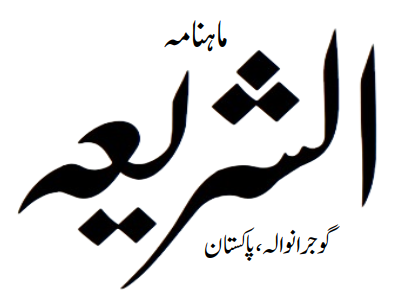عقل حاکم اور عقل خادم کا امتیاز
محمد عمار خان ناصر
زنا یعنی جنسی تسکین کو معاشرتی حدود وقیود سے مقید کیے بغیر جائز قرار دینے کے حوالے سے بعض مسلمان متکلمین نے یہ دلچسپ بحث اٹھائی ہے کہ شرعی ممانعت سے قطع نظر کرتے ہوئے، کیا یہ عمل عقلا بھی قبیح اور قابل ممانعت ہے یا نہیں؟ اس ضمن میں حنفی فقیہ امام جصاص اور شافعی فقیہ امام الکیا الہراسی کے ہاں دو مخالف زاویہ ہائے نگاہ کی ترجمانی ملتی ہے۔ جصاص کا کہنا ہے کہ زنا عقلا قبیح ہے، کیونکہ اس کی زد بچے کے نسب اور کفالت وغیرہ کے معاملات پر پڑنا ناگزیر ہے، اس لیے ان سوالات سے مجرد کر کے مرد وعورت کے باہمی جنسی استمتاع کو درست قرار دینا انسانی معاشرے کے مصالح کے لحاظ سے عقلا بھی درست نہیں۔
الکیا الہراسی اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ نسب کے ثبوت کی ضرورت کچھ شرعی احکام پر عمل کے لیے پیش آتی ہے، اگر وہ نہ ہوں تو محض عقلا نسب کی پہچان لازم نہیں۔ رہا یہ سوال کہ پھر بچے کی پرورش اور کفالت کا کون ذمہ دار ہوگا تو الکیا الہراسی کہتے ہیں کہ اگر بچے کا باپ معلوم ہو تو بھی اس کے نطفے سے بچے کی پیدائش ہونے سے عقلا یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی کفالت کا بھی وہی ذمہ دار ہو۔ یہ ذمہ داری بھی شرعا ہی لازم ہے، جبکہ شرعی حکم نہ ہونے کی صورت میں لوگ دوسرے عقلی طریقوں سے اس کی تدبیر کرنے کے پابند ہوتے کہ نسل انسانی کے بقا کو کیسے یقینی بنائیں۔ اس استدلال کی روشنی میں الکیا الہراسی یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر شرعی حکم نہ ہو تو زنا عقلا قبیح نہیں، بلکہ بالکل جائز ہے، کیونکہ عورت کی رضامندی سے اس سے جنسی استمتاع کرنے میں نہ تو دونوں میں سے کسی کا نقصان ہے اور نہ یہ ظلم ہے۔ اس کی تائید میں الہراسی اہل عرب کے عرف کا حوالہ بھی دیتے ہیں جن کے ہاں زمانہ جاہلیت میں زنا اور اس سے حصول اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں۔
جصاص اور الکیا الہراسی کے مذکورہ اختلاف سے ہمارے سامنے عقل کی ان دو نوعیتوں کے امتیاز کو سمجھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے جس کا ذکر معاصر عرب فلسفی عابد الجابری نے اپنی معروف کتاب ’’تکوین العقل العربی“ میں فرانسیسی فلسفی آندرے لالاند کے حوالے سے کیا ہے۔ لالاند نے عقل کی ان دو صورتوں کو فرانسیسی میں La raison constituante اور La raison constituee کا عنوان دیا ہے جس کا ترجمہ عابد الجابری عربی میں ’’العقل السائد“ اور ’’العقل الفاعل“سے کرتے ہیں۔ اردو میں ہم انھیں، بالترتیب، ’’ عقل حاکم“ اور ’’عقل خادم“سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ’’ عقل حاکم“ سے مراد وہ تمام اساسی تصورات، عقائد اور اصول وقواعد ہوتے ہیں جو کسی قوم میں عمومی طور پر مانے جاتے ہیں، جبکہ ان کی روشنی میں زندگی کے روز مرہ امور میں جس عقل کو استعمال کرتے ہوئے مخصوص نتائج تک پہنچا جاتا ہے، وہ ’’ عقل خادم“ ہوتی ہے۔
دوسرے لفظوں میں ’’ عقل خادم“ صرف اخذ نتائج کی صلاحیت کا عنوان ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور یہ صلاحیت تمام انسانوں میں ایک جیسی اور مشترک ہوتی ہے، جبکہ ’’ عقل حاکم“ کائنات، زندگی اور معاشرت وغیرہ سے متعلق ان بنیادی تصورات کا مجموعہ ہوتی ہے جنھیں کوئی قوم یا تہذیب مختلف اسباب سے اختیار کر لیتی ہے اور پھر انھی کے تحت تمام جزوی نتائج اخذ کرتی چلی جاتی ہے۔ عقل خادم کے برعکس، عقل حاکم کا سارے انسانوں میں مشترک ہونا ضروری نہیں، بلکہ مختلف قوموں اور تہذیبوں کی عقل حاکم مختلف ہو سکتی ہے۔ جب ہم ’’یونانی عقل“، ’’مسلم عقل“ اور ’’مغربی عقل“ جیسی تعبیرات استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی عقل حاکم ہوتی ہے، کیونکہ عقل خادم کی سطح پر ایسے کسی قومی یا تہذیبی امتیاز کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
اس تنقیح کی روشنی میں زنا کے عقلی جواز یا عدم جواز کے حوالے سے جصاص اور الکیا الہراسی کے اختلاف کو سمجھیے تو جصاص دراصل ’’عقل خادم“ کی سطح پر زنا کی عقلی قباحت کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں جس میں نسب کی حفاظت، رشتوں کی حرمت اور صلہ رحمی وغیرہ کی ذمہ داریاں پہلے سے تسلیم شدہ ہیں یعنی ’’ عقل حاکم“ کا حصہ ہیں اور ان کو مان لینے کے بعد زنا کی قباحت واقعتا عقلی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف الکیا الہراسی سوال کو عقل متحرک سے اٹھا کر ’’ عقل حاکم“ کی سطح پر لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس سطح پر اگر شریعت کے حکم کو فیصلہ کن حیثیت میں نہ مانا جائے تو بتائیے، کون سی چیز ہے جو صرف عقل کی بنیاد پر ایک اساسی اصول کے طور پر یہ طے کرتی ہو کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے نسب کی حفاظت اور خاندان کی تشکیل کا طریقہ ہی واحد اور لازم طریقہ ہے؟
لالاند نے ’’عقل حاکم“ اور ’’عقل خادم“ کا فرق واضح کرتے ہوئے ایک بہت اہم بات یہ بھی کہی ہے کہ ’’عقل حاکم“ کی تشکیل بھی ’’عقل خادم“ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی کوئی قوم مشاہدہ اور استنتاج واستنباط کی مشترک انسانی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے حیات وکائنات سے متعلق کچھ بنیادی نتائج تک پہنچتی ہے۔ پھر اصول وتصورات کا یہ مجموعہ اس کے لیے ’’عقل حاکم“ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور بعد کے مراحل میں اس کی ’’عقل خادم“ خود اپنی ہی تشکیل دی ہوئی ’’عقل حاکم“ کے تحت اور اسی کے دائرے میں مسائل واحکام اخذ کرنے کا وظیفہ انجام دیتی رہتی ہے۔ تفہیم کے لیے، عقل کے اس دوہرے عمل کو دستوری زبان میں آئین وضع کرنے اور پھر اس کی روشنی میں قانون سازی کے عمل سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ایک خود مختار پارلیمان کسی نئے ملک کی تشکیل کے مرحلے میں ملک کے نظم ونسق سے متعلق ایک بنیادی دستوری ڈھانچہ وضع کرتی ہے جو اس کی اپنی ہی تخلیق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی پارلیمان انھی دستوری حدود وقیود کے دائرے میں قانون سازی کے عمل کو جاری رکھتی ہے۔
یہاں دو سوال اہم ہیں:
ایک یہ کہ اگر عقل خادم کسی بھی مرحلے میں معطل نہیں ہوتی اور ’’عقل حاکم“ کی تشکیل بھی اسی کی مرہون منت ہوتی ہے تو پھر عقل حاکم اور عقل خادم کے امتیاز کی سرے سے ضرورت اور معنویت ہی کیا ہے؟ یعنی اس سارے عمل کو ہم سادہ طور پر ’’عقل “ ہی کی سرگرمی سے کیوں تعبیر نہیں کر دیتے؟
دوسرا یہ کہ عقل خادم کی تعریف اگر یہ ہے کہ یہ ’’مانے ہوئے“ مفروضات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے تو سوال یہ ہے کہ ’’عقل حاکم“ کی تشکیل کے بعد تو ’’عقل خادم“ کے لیے نقطہ حوالہ (یعنی پوائنٹ آف ریفرنس) ’’عقل حاکم“ بن جاتی ہے، لیکن عقل حاکم کی تشکیل کرتے ہوئے عقل کن بنیادوں پر انحصار کرتی ہے، یعنی خود عقل حاکم کی تشکیل کا عمل، عقل کن اصولوں کی روشنی میں انجام دے پاتی ہے؟
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عقل خادم، ان دونوں مرحلوں میں کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کے تحرک کی نوعیت جوہری طور پر مختلف ہوتی ہے۔ عقل حاکم کے دائرے میں آنے والے سوالات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:
ایک حصہ وہ ہے جس میں عقلی تحرک کی غایت درپیش سوالات کو مستقل بنیادوں پرطے کرنا ہوتا ہے اور یہ سرگرمی وجودی سطح پر اوربہت ہی فوری نوعیت کی ہوتی ہے۔ عقلی سرگرمی کا یہ ہنگامی پن انسانی شعور کی ساخت اور اس کے وجودی احوال، دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ انسانی شعور زندگی کی معنویت سے متعلق کچھ بنیادی سوالات کا فوری اور فیصلہ کن جواب چاہتا ہے اور اسے زیادہ لمبے عرصے تک موخر رکھنے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ تاخر کا یہ مرحلہ وجودی بے چینی کا مرحلہ ہوتا ہے جسے مستقل طور پر برداشت کرنا شعور انسانی کی طاقت سے باہر ہے۔ پھر اپنے وجودی احوال کے لحاظ سے انسان کو ٹھوس مادی نوعیت کے مطالبات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے اور ان کے روبرو اپنی سعی وکاوش کو رو بہ عمل کرنے کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ بنیادی سوالات کا ایک متعین جواب طے کیا جا چکا ہو۔
پس ایک تارک الدنیا سادھو یا ایک محو تفکر فلسفی تو یہ کر سکتا ہے کہ ہمیشہ ان سوالات پر مراقبے کی کیفیت میں رہے، لیکن معاشرت کی سطح پر زندگی کا تسلسل قائم رکھنے کے تقاضے بنیادی سوالات کے حوالے سے گومگو کی کیفیت میں پورے نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ اس مرحلے پر عقل مجبور ہوتی ہے کہ سوالات کا ایک جواب طے کرے اور پھر اسے ’’مفروغ عنہ“ قرار دے کر اگلے مراحل کی طرف متوجہ ہو جائے جو لامتناہی اور تسلسل وتغیر سے عبارت ہیں۔ جوابات کا یہ مجموعہ ’’عقل حاکم“ کا وہ بنیادی حصہ قرار پاتا ہے جو اگرچہ عقل خادم ہی کی سرگرمی سے وجود پذیر ہوتا ہے، لیکن خود عقل خادم انھیں ایک دفعہ طے کر کے اور مابعد کی ساری سرگرمیوں کے لیے بنیاد کا درجہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہتی ہے، اس لیے اسے ایک الگ کیٹگری شمار کرنا منطقی اصولوں کا ایک لازمی مقتضا ہے۔
عقل حاکم کے دائرے میں تصورات ومسلمات کا دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس کی تشکیل پہلے حصے کی طرح urgent نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل تاریخی سفر طے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر عالم غیب پر یقین، انسانی معاملات کا کسی ماورا ہستی کے ارادہ ومنشا کے تابع ہونا اور موت کے بعد کسی نہ کسی صورت میں زندگی کے تسلسل وغیرہ جیسے تصورات اگر عقل حاکم کے پہلے دائرے سے متعلق ہیں تو انسانی معاشرت کی تنظیم کی بنیاد بننے والے مختلف تصورات اور اصول واقدار کو ہم عقل حاکم کے دوسرے دائرے میں شمار کر سکتے ہیں جنھوں نے معاشرت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ خاص شکل اختیار کی ہے اور بسا اوقات صدیوں کے سفر کے بعد ان تصورات کے مجموعے نے وہ خاص سانچہ بنا دیا جسے کسی قوم یا تہذیب کا امتیازی انداز فکر یا طرز زندگی سمجھا جاتا ہے۔
دوسرا سوال جو ہماری موجودہ گفتگو کے سیاق میں بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہے کہ ’’عقل حاکم“ کی تشکیل کے لیے وہ کون سے شعوری وسائل ہیں جو عقل خادم کو دستیاب ہوتے ہیں اور وہ کون سے عوامل ہیں جو ان شعوری وسائل کی مدد سے متعین جوابات تک پہنچنے کے عمل کو ایک خاص رخ دینے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں؟ خاص طور پر یہ کہ انسانی شعور کے عمومی وسائل وآلات (وجدانی احساسات، جذبات، منطقی تصورات، محسوسات وتجربات) کے علاوہ مذہبی علم یا وحی کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے یا تاریخی طور پر رہا ہے اور اس خاص ذریعہ علم کی، عام انسانی ذرائع علم کے ساتھ تعامل کی نوعیت کیا ہے؟
اس سوال کا جواب ٹھیک طریقے سے سمجھ لینا اس اختلاف کے ممکنہ حل کی بھی ایک کلید فراہم کرتا ہے جو عقل وشرع کے باہمی تعلق کے حوالے سے مسلمان متکلمین کے مابین پایا جاتا ہے۔ ہماری رائے میں اس بحث میں عقل حاکم اور عقل خادم کا امتیاز بہت بنیادی ہے اور اس نکتے پر کماحقہ توجہ نہ دیے جانے کے باعث یہ سوال اسلامی علمیات میں کافی الجھ سا گیا ہے۔ ان شاء اللہ کسی آئندہ نشست میں اس پر نسبتا تفصیل سے کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔
اردو تراجم قرآن پر ایک نظر (۷۲)
مولانا امانت اللہ اصلاحی کے افادات کی روشنی میں
ڈاکٹر محی الدین غازی
(222) لِلَّذِینَ اَحسَنُوا فِی ھَذہِ الدُّنیَا حَسَنَۃ کا ترجمہ
یہ جملہ قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے۔ اس جملے میں ”فِی ھذِہِ الدُّنیَا“ کو اگر ”اَحسَنُوا“ سے متعلق مانیں گے تو ترجمہ ہوگا: جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔اور ”فِی ھذِہِ الدُّنیَا“ کو اگر ”حَسَنَۃ“ کی خبر مقدم مانیں گے تو ترجمہ ہوگا: ”جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں نیک بدلہ ہے“۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور سے اردو مترجمین نے دونوں جگہ الگ الگ ترجمہ کیا ہے:
(1) وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوا مَاذَا اَنزَلَ رَبُّکُم قَالُوا خَیرًا لِّلَّذِینَ اَحسَنُوا فِی ھذِہِ الدُّنیَا حَسَنَۃ وَلَدَارُ الآخِرَۃ خَیر وَلَنِعمَ دَارُ المُتَّقِینَ۔ (النحل: 30)
”دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ”بہترین چیز اتری ہے“، اِس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اِس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا “۔(سید مودودی)
”جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے“۔ (فتح محمد جالندھری)
”جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے“۔ (محمد جوناگڑھی)
”جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے“۔ (امین احسن اصلاحی)
”جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے“۔ (احمد رضا خان)
(2) قُل یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُم لِلَّذِینَ اَحسَنُوا فِی ھذہِ الدُّنیَا حَسَنَۃ وَاَرضُ اللَّہِ وَاسِعَۃ إنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ اَجرَھم بِغَیرِ حِسَابٍ۔ (الزمر :10)
”کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے“ (جوناگڑھی)
”جن لوگوں نے اِس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے“۔ (سید مودودی)
”جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے“۔ (فتح محمد جالندھری)
”جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے“۔(محمد جوناگڑھی)
”جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے (آخرت میں) نیک صلہ ہے“۔ (امین احسن اصلاحی)
”جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے“۔ (احمد رضا خان)
سورة الزمر والے جملے کا درست ترجمہ سورة النحل والے جملے کی روشنی میں متعین ہوجاتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے بعد وَلَدَارُ الآخِرَۃ خَیر سے یہ بات طے ہوجاتی ہے کہ حَسَنَۃ سے مراد دنیا کی بھلائی ہے۔ سورة النحل کی درج ذیل آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے:
وَالَّذِینَ ھاجَرُوا فِی اللَّہِ مِن بَعدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّھم فِی الدُّنیَا حَسَنَۃ وَلَاَجرُ الآخِرَۃ اَکبَرُ لَو کَانُوا یَعلَمُونَ۔ (النحل: 41)
”اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ (اسے) جانتے“۔ (فتح محمد جالندھری، کاش کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔)
اس جائزے میں ایک دلچسپ بات تو یہ سامنے آئی کہ اکثر مترجمین نے سورة النحل والے جملے کا ترجمہ تو سیاق کلام کے مطابق کیا ہے، لیکن تقریباً ان تمام مترجمین نے سورة الزمر والے جملے کا ترجمہ اس سے مختلف کردیا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ مولانا احمد رضا خان نے دونوں مقامات پر عام مترجمین سے مختلف ترجمہ کیا، یعنی پہلی آیت میں وہ ترجمہ کیا جو دوسروں نے دوسری آیت میں کیا، اور دوسری آیت میں وہ کیا جو دوسروں نے پہلی آیت میں کیا۔ سورة النحل میں سیاق کی واضح دلالت کے باوجود اس سے ہٹ کر ترجمہ کرنا حیر ت انگیزاتفاق ہے، جبکہ سورة الزمر میں وہی ترجمہ کیا ہے۔ سورة الزمر میں اکثر مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے، وہ اس آیت میں سیاق کلام کی دلالت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس جملے کے بعد ہی وَاَرضُ اللَّہِ وَاسِعَۃ آیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حَسَنَۃ سے مراد دنیا کی بھلائی ہے۔
مولانا امانت اللہ اصلاحی کے نزدیک دونوں مقامات پر اس جملے کا درست ترجمہ یوں ہے: ”جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی نیک بدلہ ہے“۔ اس کی ایک دلیل تو سورة النحل کی مذکورہ بالا دونوں آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور یہ ہے کہ دنیا تو ہے ہی دار العمل، اس لیے یہ کہنے سے کہ ،جس نے اس دنیا میں نیکی کی، کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنے سے کہ نیکی کرنے والے کو دنیا میں بھی نیک صلہ ملے گا، ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ نیک لوگوں کے لیے آخرت کے صلے کے ساتھ دنیا میں بھی نیک صلہ ہے۔
(223) زَوجَین کا ترجمہ
اردو میں جوڑا نر اور مادہ کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو جوڑ کہتے ہیں، نر اور مادہ کے ایک جوڑے کو عربی میں زوجین کہتے ہیں۔ اس پہلو سے درج ذیل آیتوں کے مختلف ترجموں کا جائزہ لیا جاسکتا ہے:
(1) وَمِن کُلِّ شَیئٍ خَلَقنَا زَوجَینِ لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ۔ (الذاریات: 49)
”اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو“۔ (سید مودودی)
”اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو“۔ (احمد رضا خان)
”اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو“۔ (فتح محمد جالندھری)
”اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو“۔ (طاہر القادری)
(2) وَاَنَّہ خَلَقَ الزَّوجَینِ الذَّکَرَ وَالاُنثَیٰ۔ (النجم: 45)
”اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر مادہ پیدا کیا ہے“۔ (محمد جوناگڑھی)
”اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ“۔ (احمد رضا خان، نر اور مادہ ایک جوڑا ہوا)
(3) فَجَعَلَ مِنہ الزَّوجَینِ الذَّکَرَ وَالاُنثَیٰ۔ (القیامۃ :39)
”تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت“۔(احمد رضا خان)
”پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں“۔ (سید مودودی)
”پھر اس کی دو قسمیں بنائیں (ایک) مرد اور (ایک) عورت“۔ (فتح محمد جالندھری)
(4) حَتَّیٰ إِذَا جَاءَ اَمرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلنَا احمِل فِیھا مِن کُلٍّ زَوجَینِ اثنَینِ۔ (ہود: 40)
”یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ تنو ر ابل پڑا تو ہم نے کہا ”ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو“۔ (سید مودودی)
”یہاں تک کہ کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور اُبلا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کرلے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ“۔ (احمد رضا خان)
(5) فَاسلُک فِیھا مِن کُلٍّ زَوجَینِ اثنَینِ۔ (المومنون: 27)
”تو اس میں بٹھالے ہر جوڑے میں سے دو “۔(احمد رضا خان، ہر ایک میں سے ایک جوڑا، نہ کہ ہر جوڑے میں سے دو)
”تو، تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے“۔ (محمد جوناگڑھی)
”تو سب (قسم کے حیوانات) میں جوڑا جوڑا (یعنی نر اور مادہ) دو دو کشتی میں بٹھا دو“۔ (فتح محمد جالندھری، یہاں بھی تعبیر مبہم ہوگئی ہے۔)
”تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے (نر و مادہ) بٹھا لینا“۔ (طاہر القادری)
مذکورہ تمام آیتوں میں جن لوگوں نے دو جوڑے ترجمہ کیا ہے، وہ درست نہیں۔ قسمیں ترجمہ کرنا بھی صحیح نہیں ، کیونکہ یہاں صنفی تقسیم کو بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ صنفی رشتے کو بتانا مقصود ہے جو لفظ زوجین سے ادا ہوتا ہے۔
(224) ازواج کا ترجمہ
ازواج، زوج کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال قسمیں بتانے کے لیے بھی کیا گیا ہے، اور کہیں شوہر اور کہیں بیوی کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ درج ذیل تین مقامات پر ترجمے غور طلب معلوم ہوتے ہیں:
(1) ثَمَانِیَۃ اَزوَاجٍ مِّنَ الضَّانِ اثنَینِ وَمِنَ المَعزِ اثنَینِ۔ (الانعام: 143)
”(پیدا کیے) آٹھ نر و مادہ یعنی بھیڑ میں دو قسم اور بکری میں دو قسم“۔ (محمد جوناگڑھی)
”آٹھ قسم کے جوڑے ہیں“۔ (ذیشان جوادی)
”آٹھ قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں“۔ (محمد حسین نجفی)
”آٹھ قسم کے“۔ (فتح محمد جالندھری)
”چوپایوں کی آٹھ قسموں کو لو“۔ (امین احسن اصلاحی)
”آٹھ نرو مادہ، چوپایوں کے آٹھ جوڑ، چوپایوں کے چار جوڑے“۔
(2) وَاَنزَلَ لَکُم مِّنَ الاَنعَامِ ثَمَانِیَۃ اَزوَاجٍ۔ (الزمر: 6)
”اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ نر و مادہ پیدا کیے“۔ (سید مودودی)
”اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے (آٹھ نر ومادہ) اتارے“۔ (محمد جوناگڑھی)
”اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے تھے“۔ (احمد رضا خان)
”اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے“۔ (فتح محمد جالندھری)
”اور پھر تمہارے لیے (تعداد میں) چوپایوں کے آٹھ جوڑے پیدا کیے“۔ (محمد حسین نجفی)
”اور تمہارے لیے (نر ومادہ) چوپایوں کی آٹھ قسمیں اتاریں“۔ (امین احسن اصلاحی)
And He sent down to you eight pairs of the cattle. (Qaribullah & Darwish)
and he sent down for you eight head of cattle in pairs (Yousuf Ali)
ثَمَانِیَۃ اَزوَاجٍ کا ترجمہ آٹھ جوڑے موزوں نہیں ہے، اسی طرح انگریزی کے بھی مذکورہ دونوں ترجموں کے فرق پر غور کیا جاسکتا ہے۔
(3) وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا ھب لَنَا مِن اَزوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّۃ اَعیُنٍ۔ (الفرقان: 74)
”جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے“۔ (سید مودودی)
”اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما“۔ (محمد جوناگڑھی)
and who pray "O our Sustainer! Grant that our spouses and our offspring be a joy to our eyes, (Asad)
And who say: Our Lord! Vouchsafe us comfort of our wives and of our offspring, (Pickthall)
” کسانی کہ می گویند: پروردگارا! از ہمسران و فرزندانمان مایہ روشنی چشم ما قراردہ“۔ (مکارم شیرازی)
عربی زبان میں لفظ ازواج دونوں پر صادق آتا ہے۔ انگریزی میں spouseاس کا درست مفہوم ادا کرتا ہے۔ اردو میں میری علم کی حد تک سبھی لوگوں نے اس آیت میں ازواجنا کا ترجمہ ہماری بیویاں کیا ہے۔
فارسی میں عام طور سے اس آیت میں مذکور ازواج کا ترجمہ ہمسران کیا گیا ہے، لفظ ہمسر فارسی زبان میں بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور جوڑے کے ساتھی کے لیے بھی۔
بہرحال، اس آیت میں ازواج کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے جس میں عموم ہو، اور اس دعا کی معنویت صرف شوہر کے لیے نہیں رہے بلکہ بیوی کے لیے بھی رہے۔مجھے اردو میں spouse یا زوج کی طرح بالکل موزوں لفظ نہیں ملا، تاہم انسانوں کے سیاق میں شریک حیات اور جیون ساتھی جیسے الفاظ بھی مطلوبہ مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔
خدا کی رحمت اور عدل: ایک حقیقت کے دو نام
ڈاکٹر عرفان شہزاد
فطرت الہی اور فطرت انسان کی مشترکہ اساسات اور احساسات:
فطرت الہی کو جاننے اور سمجھنے کا راستہ فطرت انسانی ہے۔
فِطْرَتَ اللَّہ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْھَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّہ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [الروم: 30]
"تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیاہے۔"
اخلاقیات اور جمالیات کے باب میں انسانوں کی فطرت میں پائے جانے والے بنیادی اور مشترکہ احساسات اور ان کی اساسات فطرت الہی پر مبنی ہیں۔ انسان اسی چیز کو اچھا اور برا سمجھتا ہے جو فطر ت الہی سے اسے ودیعت ہوا ہے۔ اس کا برعکس کہنا بھی اسی وجہ سے درست ہے کہ انسانی فطرت جسے اچھا اور برا سمجھتی ہے وہ خدا کے نزدیک بھی اچھا اور برا ہے۔ یہ ایک منصوص قضیہ ہے۔ اس کے مقابل اس فہم کا نقص یا کوئی نص ہی سے کوئی دلیل پیش کی جائے تو قابل اعتنا ہو سکتی ہے، خیال آرائی کی یہاں کوئی حیثیت نہیں۔
حسن و قبح اور عدل و ظلم کا معیار:
حسن و قبح اور عدل و ظلم معروض میں موجود تصورات نہیں ہیں، جنھیں انسان خارج سے اخذ کرتا ہے اور جن کی پابندی خدا پر بھی لازم ہو، یہ فطرت الہی سے پھوٹے تصورات ہیں ،جن کا پرتو انسانی فطرت میں آیاہے اور اس وجہ سے ان کی پیروی اور پابندی انسان خود پر لازم سمجھتا ہے۔ یہ احساسات تمام انسانیت کا مشترک ورثہ اور اثاثہ ہیں، اسی لیے یہ عالم گیر سطح پر یکساں ہیں۔
عدل و ظلم، حسن و قبح اور نیکی و بدی کے تصورات اور احساسات کی انسانی فطرت اور ذہن میں موجودگی کے بارے میں کوئی بحث نہیں، البتہ ان کی تعریف اور اطلاقی صورتوں کی تعیین میں اختلاف اور مباحثہ میں ہوتا ہے۔ فلاسفہ کے ایک محدود گروہ، جو کسی بھی تصور اور قدر کی آفاقیت اور استقلال کے قائل نہیں، کو چھوڑ کر ایسا کبھی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ طے کیا جائے کہ عدل کوئی قدر ہے بھی یا نہیں، یا ظلم کوئی تصور ہوتا ہے یا نہیں اور اسی طرح نیکی اور بدی کوئی تصور رکھتے ہیں یا نہیں۔ البتہ یہ مباحثہ ہوتا ہے کہ فلاں معاملے میں عدل کی کون سی صورت عدل کہلائے گی اور کیا چیز ظلم بن جائے گی اور یہ کہ کوئی فعل درحقیقت نیکی ہے یا نہیں۔ تعریف اور اطلاق میں اختلاف سے تصورباطل نہیں ہو جاتا۔ احساس اور تصور کی سطح پر انسانوں کا ہمہ گیر اتفاق اس پر ایک عالم گیر شاہد ہے۔
عدل و رحمت سے محبت اور ظلم اور ناانصافی سے نفرت کا تجربہ چند ماہ کے بچوں تک میں کر لیا گیا ہے1,2۔ ہمیں بچوں میں ان احساسات کو منتقل نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ان کے اندر موجود ان احساسات کے اطلاقات کے وقت ان کی ابتدائی رہنمائی کرنا ہوتی ہے۔ انھیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اچھائی اوربرائی کے احساسات کیا ہوتے ہیں، انھیں صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں چیز کیوں اچھی یا بری ہے۔ لیکن اچھا ئی اور برائی ہوتی کیا ہے، اس کو موضوع نہیں بنانا پڑتا۔ یہ اس لیے کہ ان کا علم فطرت سے وہ اسی طرح لے کر آتے ہیں جیسے بھوک پیاس اور زبان سیکھنے اور بولنے کی جبلت لے کر آتے ہیں۔ ماحول سے وہ تصورات کے اطلاقات سیکھتے ہیں، تصورات نہیں سیکھتے، وہ پہلے سے ان میں موجود ہوتے ہیں۔
خدا کی رحمت و عدل:
حسن و قبح کے یہ مشترک احساسات اور ان کی اساسات، انسانوں کی ایک دوسرے کے درمیان اورخدا اور بندے کے درمیان مکالمہ اور مخاطبہ کی بنیاد اور ذریعہ ہیں۔ خدا اور انسان کی فطرت کے درمیان یہ احساسات اور ان کی اساسات کا اشتراک اگر نہ ہو تو بندوں کو یہ باور کرانے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا کہ خدا رحم اور عدل کرنے والا ہے اور ظلم نہیں کرتا، جب کہ رحم، عدل اور ظلم کے مفاہیم اور ان کا میرٹ وہ نہیں جو انسان سمجھ سکتے ہیں۔
خدا کا رحم اور عدل کرنا، ظلم نہ کرنا اور اپنے وعدے پورے کرنے کے مفاہیم وہی ہیں جو انسانی عقل و فطرت سمجھتی ہے۔ خدا کے ان فرامین کے باوجود خدا کو کسی ضابطے کا پابند نہ سمجھنا یا انسانی فہم میں پائے جانے والے ان ضابطوں سے اسے بے نیاز سمجھنا بے بنیاد عقلی تجاوز ہے۔ یہ غلط فہمی خدا پر بھروسے اور اس بھروسے پر اس کی اطاعت کرنے اور اس پر امید جزر کرنے اور اس کے ڈر سے اس کی معصیت سے بچنے اور معصیت پر سزا کے خوف کی ساری خدائی اسکیم کو عملاً معطل کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ خدا کو ظالم یا لاابالی سمجھ کر اس سے ناراض ہو جانے یا اسےنظر انداز کرنے یا اباحیت کی صورت میں نکلنا بدیہی ہے۔
خدا کی رحمت اور عدل کے اصولوں کی اطلاقی صورتوں کے پیچھے اس کے علم اور حکمت کا احاطہ نہ کرنے سکنے کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ خدا کے ہاں رحمت اور عدل کے مفاہیم ہی کوئی اور ہیں۔ یہ ایسی ہی غلط فہمی ہے جیسے کسی عدالتی فیصلے کی تفصیلی جانکاری کے بنا یہ سمجھ لیا جائے کہ فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوا ہوگا یا میرٹ ہی کوئی اور مقرر کیا گیا ہوگا جو عام انسانی فہم سے بالاتر کوئی تصور ہے۔
خدا کسی قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا، کیونکہ ہر قبیح ظلم ہے اور اس نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے۔ قبیح کا ارتکاب نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہے کہ قبیح کا ارتکاب کرنا اس کی شان کے لائق نہیں، یعنی وہ شان جو اس نے خود بیان کی ہے۔ قدرت ہونے کے باوجود قبیح کا اتکاب نہ کرنا خدا کو ہماری نظر میں عظیم بناتا ہے، ورنہ مجبور کے لیے قبیح کا ارتکاب نہ کرنا کوئی کارنامہ نہیں۔ یہی بات اس کو مہربان خدا بناتی ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، ورنہ صرف عظمت صرف خوف اور خشیئت پیدا کرتی ہے۔
دنیا کی تخلیق اور مشیئت خداوندی:
دنیا کی تخلیق کے منصوبے کی اساس خدا کی مشیئت ہے اور اس کا مقصدبندوں پر عنایات کرنا ہے۔ یہ مشیئت خدا کی صفات کے اظہار اور اس کی ہمہ گیر عبودیت کے لیے برپا کی گئی ہے نہ کہ محض رحمت کے اظہار کے لیے۔ مشیئت رحمتِ محض نہیں بلکہ عدل کے ساتھ گندھی ہوئی ہے۔ یہ محض رحمت ہوتی تو دکھ اور تکلیف نہ ہوتے۔ دکھ اور تکلیف نہ ہوتے تو خدا کی صفات رحمت، عدل اور کرم کا ظہور نہ ہوتا۔ خدا کی اس اسکیم میں بشمول انسان سب مخلوقات کو دکھ اور تکلیف سے بھی گزرنا پڑا۔ یہ سب انسان کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ خدا کی صفات کے اظہار کےلیے بنایا گیا ہے۔
ساری کائنات خدا کے سامنے تسلیم ہے، سوائے انسان اور جنّ کے عقلی وجود کے، جسے اس نے ارادہ واختیار دے کر اپنے سامنے تسلیم ہو جانے کی دعوت دی ہے۔
دنیا میں آزمایش کا اصول:
دنیا کا نظام اصول آزمایش پر ہے جس میں عدل نہیں ہے۔ اسی سے عدل کا تقاضا پیدا ہوتا ہے جو آخرت کے برپا کرنے کو لازم بنا دیتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا عادل ہے ورنہ آخرت میں عدالت لگانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ آزمایش کا قانون عدل پر مبنی نہیں ہے۔ عدل ہو تو آزمایش نہیں ہو سکتی۔ البتہ آزمایش کے خاتمے پر جزا اور سزا کا قانون مل کر اسے مطابق عدل اور عنایت رحمت کا مظہر بناتا ہے۔
ہمارے ہاں خدا کے وکیلوں کو دنیا میں بھی خدا کا افعال اور اسکیم کو مطابقِ عدل ثابت کرنے کی فکر دامن گیر رہی جس کےلیے انھوں نے عجیب تاویلات کیں۔ انھوں نے خدا کو ظلم سے بری قرار دینے کے لیے اس کی ذات کے لیے عدل کے فطری اور معروف تصورات ہی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ خدا کی آزاد ذات پر یہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتیں اور یہ کہ یہ انسانوں کے معیارات ہیں۔ حالانکہ یہ فطرت کے معیارات تھے جنھیں خود خدا نے ودیعت کیا تھا اور انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے انسان کے ذہن میں انھیں تصورت کی بنیاد پر خود کو عدل و رحمت کرنے والا اور ظلم نہ کرنے والا قرار دیا تھا۔ ایک بار جب خدا عدل کے معروف تصور کاپابند نہ رہا تو اس کی زد پھر آخرت کے تصور عدل پر بھی پڑی اور وہاں بھی خدا عدل کے تقاضوں سے آزاد قرار دے دیا گیا۔ یہ نظریہ خدا، دین اور مسلمان تینوں سے نادان دوستی پر مبنی تھا۔ خدا لاابالی ٹھرا جس کو چاہے سزا دے جس کو چاہے جزا دے، دین کے اوامر و نواہی کی پاسداری کارِ اضافی قرار پائے۔ خدا کے وعدے اور وعیدیں دونوں کے پورا کرنے کی پابندی خدا پر نہیں رہی۔ خدا سےامید اور خوف دونوں کی بنیاد ہی نہ رہی تو اعمال اور اطاعت اپنا جواز کھو بیٹھے۔ مسلم ذہن خدا کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہو گیا۔ خداعنایت کر دےتو نجات مل جائے گی مگر خدا قہر نازل کر دے تو کیا کیا جائے، اس سے بچنے کے لیے اس نے سہارے تلاشے اور تراشے یا وہ سرے سے مایوس ہو کر رہ گیا۔
میرٹ کا اصول اور تقاضے:
حقیقت خدا کے اپنے بیان میں اس کے برعکس تھی۔ اس کی رحمت نے چاہا کہ انسانوں کو ابدی نعمتوں سے نوازے۔ مگر اس نوازش کو اس نے اعزاز بنا یا جسے میرٹ پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میرٹ کے لیے اس نےانسان کو اچھائی اور برائی کی سمجھ اور ارادہ اور اختیار دے کر آزمایش کا قانون بنایا۔ یہ اس کی مشیئت تھی۔
آزمایش کا میرٹ خدا کی شان اور عنایات کے مطابق نہیں، بلکہ انسان کی استطاعت کے مطابق مقرر کیا گیا:
لَا يُكَلِّفُ اللَّہُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا [البقرة: 286]
اللہ کسی پر اُس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
یہ رحمت ہے، لیکن یہی عدل ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم میڑک کے طالب علم سے ماسڑز کی سطح کا امتحان نہیں لیتے۔
اس آزمایش کے لیے انسان کی تخلیق کا مقصد اسے میرٹ کی بنیاد پر کامیاب کرنا ہے:
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاۃ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور [الملك: 2]
"(وہی) جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور درگذر فرمانے والا بھی۔"
عدل سے مراد مساوات اور یکسانیت نہیں ہے۔ میرٹ کا سب کے لیے یکساں ہونا ظلم ہے، عدل نہیں۔ بے لاگ اور اندھا انصاف کرنا اور مستحق کو رعایت نہ دینا ظلم ہے عدل نہیں۔ مستحق کے لیے سفارش قبول کرنا بھی عدل کا تقاضا ہے۔ دوسرے پہلو سے دیکھیے تو یہی سب رحمت ہے۔ یہ سفارش نہ بے قاعدہ ہے نہ بے محابا اور نہ اتنی زور آور کہ خدا کو فیصلہ بدلنے پرمجبور کر سکے ورنہ یہ ظلم کی وکالت بن جائے گا:
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَۃ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَہُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا [النبأ: 38]
اُس دن، جب فرشتے اور جبریل امین، سب اُس کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اُس دن، جب وہی بولیں گے جنھیں رحمن اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں۔
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَہ إِلَّا بِإِذْنِہ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِہِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة: 255]
"کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر اُس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے۔ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے اور وہ اُس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، مگر جتنا وہ چاہے۔ "
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِہِ الشَّفَاعَۃَ إِلَّا مَنْ شَھَدَ بِالْحَقِّ وَھُمْ يَعْلَمُون [الزخرف: 86]
اُس کے علاوہ یہ جنھیں پکارتے ہیں، وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ اُس کو جانتے بھی ہوں گے۔
یعنی جن کو سفارش کی اجازت ملے گی وہ خلاف حق کچھ نہیں کہیں گے۔
آزمایش کے قانون کا لازمی نتیجہ کامیابی کے ساتھ ناکامی، نیکی کے ساتھ بدی اور عدل کے ساتھ ظلم کی صورت میں نکلنا تھا۔ یہ سب اس آزمایش کی اسکیم کا حصہ ہے۔ اس سے رحمت اور عدل کا تقاضا پیدا ہوا کہ نیکوکاروں کو پورا صلہ ملے جو آزمایش گاہ میں نہیں ملتا اور مظلوموں کی داد رسی ہو جو یہاں نہیں ہو پاتی۔ یہ رحمانیت کا تقاضا تھا جو عدل پر منتج ہوتا ہے۔ یوں آخرت کا جواز پیدا ہوا جہاں پورا عدل بروے کار لایا جائے۔ ایسا نہ ہو تو دنیا اپنی تمام تر تکوینی معنوییت کے باوجود عبث قرار پاتی اور خدا لاابالی ظالم، اور غیر حکیم ثابت ہوتا ہے جس نے نیکوکاروں کو پورا صلہ نہیں دیا، ہوس کے بچاریوں کو زیادہ پرلطف زندگی گزارنے کا موقع دیا اور مظلوموں کی داد رسی کا انتظام نہ کر کے ظالم کی حوصلہ افزائی کی۔
ظالم کو معافی اور رعایت دینا مظلوم کے حق میں ظلم ہے۔ ظالم و مظلوم دونوں خدا کی رحمت و عنایت کے مستحق ٹھریں تو یہ ظالموں کی حوصلہ افزائی ہے جس سے ان کو مظلوم پر زیادتی کرنے کی شہ ملتی ہے کہ اس کے لیے بھی امکان نجات و عنایت موجود ہے۔ یوں خدا ظالم کا سہولت کار بن کر ظالم ٹھرتا ہے، جب کہ اس نے خود پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔
اس لحاظ سے دیکھیے تو رحمت اور عدل ایک دوسرے میں ممزوج اور مترادف ہیں اور رحمت یعنی کہ عدل کرنا خدا نے خود پر لازم قرار دے دیا ہے۔
قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّہِ كَتَبَ عَلَی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَۃ لَا رَيْبَ فِيہ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَھُمْ فَھُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [الأنعام: 12]
"اِن سے پوچھو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، وہ کس کا ہے؟ کہہ دو، اللہ ہی کا ہے۔ اُس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اِس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنھوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے۔"
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَۃِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّۃٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِھَا وَكَفَی بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء: 47]
"روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے۔ پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہو گا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہو گا تو ہم اُس کو لا موجود کریں گے۔ اورہم (لوگوں کا) حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔"
میرٹ پر سب کو داخلہ مل جانا میرٹ پر آنے والوں کے ساتھ فریب ہے۔ نیک و بد سب خدا کی رحمت اور عنایت سے بہرہ مند ہوں تو یہ نیکو کاروں کے ساتھ دھوکا ہے کہ نفس کے تقاضوں کے خلاف خدا کی مرضیات پر چلنے والے، نفس کی پجاریوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں۔ دونوں کے نیک اور بد انجام میں فرق ہونا رحمت بھی ہے اور عدل بھی۔ چنانچہ خدا نے یہی بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا:
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيہ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيہ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَۃ إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَۃِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْھُمْ أَيُّھُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ [القلم: 35 - 40]
"(تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہو گا) تو کیا ہم اپنے فرماں بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمھیں کیا ہوا ہے، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمھارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ وہاں تمھارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرو گے؟ کیا تمھارے لیے ہم پر کوئی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ تمھارے لیے وہی کچھ ہے جو تم حکم لگاؤ گے؟ اِن سے پوچھو کہ اِن میں سے کون اِس کا ذمہ لیتا ہے؟"
اس لحاظ رحمت اور عدل کی حقیقت ایک ہے۔ ایسی رحمت جو عدل سے بے نیاز ہو، خود رحمت کے منافی ہے۔ رحمت اور عدل ایک دوسرے کو متوازن نہیں کرتے، نہ یہ متخالف اور متصادم ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ناقص بلکہ باطل ہو جاتا ہے۔ کامل عدل رحمت کے بغیر ممکن نہیں اور رحمت بغیر عدل کے نہیں ہے۔
اس آزمایش میں میرٹ کی شرط عدل پر مبنی ہے۔ البتہ رحمت الہی کا تقاضا ہوا کہ انسان کی خلقی مجبوریاں جیسے نسیان اور جذبات کے تصرف، اور نفس اور شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں رعایات بھی دی جائیں اور ان موانعات کے مقابلے میں میرٹ پر آنے کے لیے سہولت بھی مہیا کی جائے۔ چنانچہ، علم و عمل میں نسیان اور دیانت دارانہ خطا پر بلا مشروط معافی اور جذبات کی مغلوبیت میں جرم کا ارتکاب اور اس کے فورا بعد ندامت پر لازمی درگزر کا اصول بتایا گیا:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرۃ : 286]
پروردگار، ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اُس پر ہماری گرفت نہ کر۔
إِنَّمَا التَّوْبَۃ عَلَی اللَّہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَھَالَۃٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّہُ عَلَيْھِمْ وَكَانَ اللَّہُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 17]
اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری اُنھی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔سو وہی ہیں جن پر اللہ عنایت کرتا اور اُن کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ علیم وحکیم ہے۔
روز قیامت تثلیث کے قائلین مسیحیوں کے بارے میں خدا اور مسیح علیہ السلام کے درمیان مکالمے کے آخر میں خدا نے اپنا واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ ان میں سے جو لوگ اپنے قول و قرار اور عہدو میثاق میں سچے ثابت ہوئے اور اُنھوں نے جانتے بوجھتے کسی گم راہی پر اصرار نہیں کیا، بلکہ جو کچھ سمجھا، دیانت داری کے ساتھ سمجھا، اُس میں دانستہ کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں کی، پھر اپنی استطاعت کے مطابق اُس پر عمل پیرا رہے، اُن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
اِن تُعَذِّبہُم فَاِنَّہُم عِبَادُکَ وَاِن تَغفِر لَہُم فَاِنَّکَ اَنتَ العَزِیزُ الحَکِیمُ قَالَ اللَّـہ ھٰـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِينَ فِيھَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّـہُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْہ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [المائدہ : 119]
اب اگر آپ اُنھیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔اللہ فرمائے گا: یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی اُن کے کام آئے گی۔ اُن کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔زمین و آسمان اور اُن کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
خدا کی رحمت عدل سے تجاوز تب کرتی ہے جب ایسا کرنا خلاف عدل نہ ہو
خدا کی رحمت عنایت کی صورت میں عدل سے تبھی تجاوز کرتی ہے جب وہ عدل کے خلاف نہ ہو۔خدا کی رحمت اگر مجرموں کو دنیا میں فوراً سزانہ دے اور بار بار موقع دے،3 یا آخرت میں سزا نہ دینے کا یاکچھ سزا دے کر ابدی سزا نہ دینے کا فیصلہ کرلے4تو رحمت کا یہ مظہر عدل کے منافی نہیں، مگر یہ کہ وہ ان پر عنایات بھی کرے یہ عدل کے منافی ہے۔ نیکوکار انعام یافتگان کے مقابل ظالموں اور فاسقوں کی محرومی خود بہت بڑی سزا ہے جب کہ انعام یافتگان کی نعمتیں ابدی ہوں اور محروموں کی محرومی بھی ابدی ہو۔ خدا اگر ظالموں کو فنا کر دے تو یہ بھی ان کے حق میں رحمت ہے اور یہ عدل کے خلاف نہیں، اس لیے درست بھی ہے۔ یہ سزا بہت ہے کہ انھیں ابدی عنایات نہیں ملیں۔ یہ سب کرنا خدا کا اختیار (عزیز) ہے مگر خلاف عدل نہیں اور مظہر رحمت بھی ہے۔
سزا اور جزا کے اعلان کی پاسداری میں ایک فرق ہے۔ سزا کے اعلان کی پاسداری نہ کرنا غلط نہیں۔ وعدہ اور وعید میں سے یہ وعدہ ہے کہ جسے اگر پورا نہ کیا جائے تو یہ بد اخلاقی ہے، اس لیے قبیح ہے اور خدا قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا، لیکن وعید پر باوجود قدرت اور اختیار کے عمل نہ کرناعنایت سمجھاجاتا ہے اس لیے حسن ہے۔ چنانچہ خدا اگر کسی کو سزا نہ دے تو اسے کسی میعاد کی خلاف ورزی نہیں کہا جائے گا۔ البتہ وہ عنایت بھی کرے یہ خلاف عدل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔
یہیں سے انبیا کی مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کا جواز سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر یہ عنایت کے مستحق نہیں، تو کم از کم سزا سے نجات دے دی جائے اور خدا اس کا اختیار رکھتا ہے:
إِذْ قَالَ إِبْرَاھِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّھُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّہ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [إبراھيم: 35، 36]
(یہ ابراہیم کی اولاد ہیں )۔ اِنھیں وہ واقعہ سناؤ، جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار، اِس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اِس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ پروردگار، اِن بتوں نے بہت لوگوں کو گم راہی میں ڈال دیا ہے۔ (یہ میری اولاد کو بھی گم راہ کر سکتے ہیں )، اِس لیے جو (اُن میں سے) میری پیروی کرے، وہ تومیرا ہے اور جس نے میری بات نہیں مانی، اُس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔
إِنْ تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة: 118]
اب اگر آپ اُنھیں (مسیح علیہ اور ان کی والدہ کو بھی معبود بنانے والوں کو) سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔
چنانچہ اگر خدا ظالموں کو عنایات اور انعامات سے محروم کرنے پر اکتفا کر لے یا انھیں فنا کر ڈالے5تو یہ خلاف عدل نہیں کہ مظلوم کی داد رسی ظالم کو سزا دینے پر منحصر نہیں، مگر ظالم پر عنایت خلاف عدل ظالم کی حوصلہ افزائی ہے۔ اسی طرح میرٹ پر آنے کے بعد خدا کی بے پایاں عنایات کا تعلق بھی رحمت سے ہے، مگر یہ عدل کے منافی نہیں، اس لیے روا ہے۔ یہاں بھی لیکن عدل بالکلیہ خارج نہیں ہوا۔ چنانچہ کسی غیر نبی پر خواہ کتنی عنایات ہو جائیں، وہ نبی کا درجہ نہیں پا سکتا۔
دنیا میں البتہ عنایات جتنی زیادہ ہوتی ہیں میرٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
وحی سے مزید سہولت کی عنایت اور میرٹ میں اضافہ
وحی کے علم کے ذریعے سے انسانوں کے لیے عدل کے قیام میں مزید سہولت بھی فراہم کی گئی:
اللَّہُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ [الشورى: 17]
"اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور (اِس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے) اپنی میزان نازل کر دی ہے۔"
وحی کو ہدایت اور نور کہا گیا جو نفس اور جہالت کے ظلمات سے انسان کو عقیدے اور عمل کی درست اور متوازن راہ دکھائے۔
وحی کی عنایت ہوتے ہی انسان کے میرٹ میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہر فرد کی جانچ اس کے میسر علم کے بقدر ہونے کا عادلانہ اصول مقرر ہوا تو وحی کے حاملین کا میرٹ بھی غیر حاملین سے زیادہ مقرر ہوا۔ عنایت (رحمت) اور عدل یہاں بھی باہم ممزوج ہیں۔ وحی کو براہ راست پانے والے انبیا کے محاسبے اور میرٹ کا معیار استدلال کی راہ سے وحی وصول کرنے والے عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں بلند رکھا گیا۔ یونس علیہ السلام وحی کے براہ راست مخاطب تھے، انھیں ایک خطا پر مچھلی کے پیٹ میں بند کردیا گیا، پھر جب ندامت اور توبہ کی تو معافی ملی ورنہ وہی ان کا مدفن قرار پا گیا تھا۔ ادھر ان کی قوم شرک جیسے شدید گناہ اور اس پر سرکشی کے باوجود بغیر سزا کے محض توبہ کرنے پر معافی کی مستحق قرار پائی۔
خدا کی رحمت اس کے غضب پر بڑھی ہوئی ہے ،اس کے عدل پر نہیں۔
اخلاق و شرع اور عدل و رحمت:
کائنات کاتکوینی نظا م میزان عدل پر قائم ہے۔ اس میں معمولی تغیر عظیم فسادکا سبب بنتا ہے۔ انسان کو ارادہ اور اختیار، نسیان اور جہالت کے عوارض اور نفس اور شیطان کی ترغیبات دے کر نظام زندگی میں اسی میزان عدل کو قائم کرنے کی آزمایش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اس میں فطرت اور وحی کی رہنمائی سے انحراف فساد کا سبب بنتا ہے:
وَالسَّمَاءَ رَفَعَھَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ [الرحمن:7، 8، 9]
"اور اُس نے آسمان کو اونچا کیا اور اُس میں میزان قائم کر دی کہ (اپنے دائرۂ اختیار میں) تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو۔اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ "
یہ اخلاقیات اور قانون کی میزان ہے۔ قانون کی بنیاد بھی اخلاقیات ہوتی ہے۔اس میزان کے توازن میں کوتاہی اور خلاف ورزی بھی فسادات کا سبب بنتی ہے۔ یہی فساد آخرت تک ممتد ہو جاتا اور انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے خسران میں ڈال دیتا ہے۔
اخلاق و شرع دونوں میں وحی کی ہدایات اور احکامات عدل اور رحمت کا امتزاج ہیں۔ عقیدے کے باب میں خدا کے وجود کو تسلیم کرنا اور اس پر بنا پر اس کی عبادت کرنا عقل و فطرت کا تقاضا بن کر سامنے آتا ہے تو دیانت داری کا تقاضا اسے تسلیم کرتے ہوئے اس کے مقتضیات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہی عدل ہے۔ وحی اسی عقلی استدلال کی طرف متوجہ کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ یہ سہولت خدا کی رحمت سے صادر ہونے والی عنایت ہے تاکہ انسان عقل کی عدالت کا فیصلہ تسلیم کرے۔
سماجی اخلاقیات کے باب میں سچی گواہی دینا،عداوت کے باوجود حق پر قائم رہناعدل ہے،سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، یہی میزان عدل کو قائم کرنا ہے، وحی اسی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ دعوت رحمت کا نتیجہ ہے کہ انسان عدل قائم کر سکے۔
قانون کے باب میں فرائض کو استطاعت کے ساتھ متعلق کرنا اور حالت اضطرار میں احکام میں نرمی اور گنجایش اور ان کا معاف ہو جانا عدل کے اصول پر ہے اور یہ سب رحمت کا نتیجہ اور تقاضا بھی ہے۔ ایک کو دوسرے سے الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔
انسان میں مکارم اخلاق کا حاسہ آگے بڑھ کر زیادہ اور بے لوث نیکی کرنا چاہتا ہے۔ وحی اس کی حوصلہ افزائی اور ترغیب دیتی ہے۔ یہ سراسر رحمت ہے۔ اس نیکی کا صلہ دینا البتہ عدل او رحمت کا تقاضا ہے۔
خدا کے فیصلے اعمال کی گنتی پر نہیں رویوں کی حقیقت پر کیے جائیں گے۔ یہ حکیمانہ عدل بھی ہے اور رحمت بھی۔
تسلیم و انکار کے رویوں کے دو درجے
تسلیم و انکار کے رویوں کے دو درجے ہیں: تسلیم کے دور درجےخود سپردگی (اسلام) احسان (اعلی درجے کی خود سپردگی) اور انکار حق کے در درجے غفلت پر اصرار اور سرکشی (غفلت پر اصرار میں جارحانہ رویہ دکھانا) ہیں۔ غفلت پر اصرار بھی سرکشی ہی کی ایک صورت مگر شدت اور جارحیت میں کھی سرکشی سے ایک درجہ کم ہے۔ تسلیم و انکار کے رویے کامیابی اور ناکامی کا معیار ہیں، جنھیں خدا کے علم کی روشنی میں عدل کے تقاضوں کے مطابق برتا جائے گا۔ رعایت کے مستحق رعایت پائیں گے اور میرٹ پر آنے والے بےپایاں عنایت سے سرفراز ہوں گے۔غیر مستحق اور میرٹ پر نہ آنے والے سزا کے مستحق اور اس کی عنایات سے محروم رہیں گے۔یوں رحمت اور عدل کے تقاضے پورے ہوں گے۔
خلاصہ یہ کہ خدا کی رحمت وعدل ایک کو دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اورخدا کو اس کے اصولوں پر سمجھوتہ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
حواشی
(1) https://www.youtube.com/watch?v=FRvVFW85IcU
(2) Hamlin, J., Wynn, K. & Bloom, P. Social evaluation by preverbal infants. Nature 450, 557–559 (2007). https://doi.org/10.1038/nature06288
(3) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّہُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَی ظَھْرِھَا مِنْ دَابَّۃٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُھُمْ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُھُمْ فَإِنَّ اللَّہَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا [فاطر، 45]
"لوگوں کو اُن کے اعمال پر اگر اللہ فور اً پکڑتا تو زمین کی پشت پر کسی جان دار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ اُنھیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھرجب اُن کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو لازماً پکڑتا ہے، اِس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔"
(4) َأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَھُمْ فِيھَا زَفِيرٌ وَشَھِيْقٌ خَالِدِينَ فِيھَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّۃِ خَالِدِينَ فِيھَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذ [ہود: 106 - 108]
"سو جو بدبخت ہوں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اُنھیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے۔ وہ اُسی میں پڑے رہیں گے، جب تک (اُس عالم کے) زمین و آسمان قائم ہیں، الّا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے۔ اِس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے، کر گزرنے والا ہے۔ رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے۔ وہ اُسی میں رہیں گے، جب تک (اُس عالم کے) زمین و آسمان قائم ہیں، الاّ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اُس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔"
(5) ایضا
جنت اور دوزخ کے ساتھ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کی تحدید واقع ہوئی ہے، اس سے ان کی غیر ابدی ہونے کا جو وہم پیدا ہوتا ہے اس میں سے صرف جنت سے متعلق اس وہم کو یہ کہہ کر دور کیا گیا ہے کہ یہ غیر منقطع ہوگی، مگر دوزخ کے بارے میں اس وہم کو دور نہیں کیا گیا۔
سودی نظام کے خلاف جدوجہد کا نیا مرحلہ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
وفاقی شرعی عدالت میں سودی نظام کے خاتمہ کے حوالہ سے رٹ کی سماعت طویل عرصہ کے بعد دوبارہ شروع ہونے سے ملک میں رائج سودی قوانین سے نجات کی جدوجہد نئے مرحلہ میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی تحریک انسداد سود پاکستان نے نئی صف بندی کے ساتھ اپنی مہم پھر سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
بانیٔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم و مغفور نے وفات سے چند ہفتے قبل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کا معاشی نظام مغربی اصولوں پر نہیں بلکہ اسلامی اصولوں پر استوار ہو گا مگر ان کی ہدایت کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے حالانکہ دستور پاکستان میں دوٹوک کہا گیا ہے کہ سودی نظام کو جلدازجلد ختم کر کے ملک کے معاشی نظام کو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بنایا جائے گا۔ مگر ان واضح ہدایات کے باوجود سودی نظام اور قوانین بدستور موجود ہیں اور عدالتوں میں آنکھ مچولی مسلسل جاری ہے۔ چند روز قبل وفاقی شرعی عدالت نے اس سلسلہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک درخواست کو مسترد کیا تو راقم الحروف نے ٹویٹ میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اس کا اصولی طور پر خیرمقدم ہونا چاہیے مگر ٹال مٹول اور تاخیری حربوں میں تسلسل کے باعث اب یہ تکلف ہی لگتا ہے۔
اس موقع پر سودی نظام کے خلاف جدوجہد کے معروضی تقاضوں کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جا رہی ہیں:
- عوامی ماحول میں حلال و حرام کا شعور و احساس کم ہوتا جا رہا ہے اور بے پروائی میں اضافہ ہو رہا ہے جس کا علماء کرام اور دینی اداروں کو سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے اور خطابات، بیانات، سوشل میڈیا اور دیگر میسر ذرائع سے حلال و حرام کے مسائل اور ان میں فرق کی دینی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے خاص طور پر سودی نظام کی نحوستوں سے عوام کو خبردار کرنا چاہیے۔
- تاجر برادری کی تنظیموں اور راہنماؤں کو تجارتی ماحول میں یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ تجارت کے جن شعبوں میں وہ ازخود سود سے بچ سکتے ہیں یا سود کے حوالہ سے جو چند اسلامی قوانین اس وقت موجود ہیں ان پر عملدرآمد کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ عوامی رابطہ مہم کی ضرورت ہے جو تاجر تنظیمیں اور ادارے بآسانی کر سکتے ہیں۔
- سیاسی سطح پر دستور پاکستان کی اسلامی دفعات بالخصوص سودی نظام کے خاتمہ کی دفعات پر عملدرآمد کے لیے مشترکہ جدوجہد تمام سیاسی جماعتوں بالخصوص دینی جماعتوں کی ذمہ داری ہے اور قومی سیاست میں متحرک دینی جماعتوں اور قائدین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
- وفاقی شرعی عدالت میں اس کیس کی پیروی عملی طور پر جماعت اسلامی پاکستان اور تنظیم اسلامی پاکستان کے راہنما کر رہے ہیں جن میں تحریک انسداد سود پاکستان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر فرید احمد پراچہ بھی شامل ہیں۔ ملک بھر کے وکلاء اور بار ایسوسی ایشنز کو اس کی حمایت و تعاون کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے اور ان کی اس مہم میں عملی شرکت کا اہتمام کرنا چاہیے۔
- تحریک انسداد سود پاکستان کی جدوجہد کا نیا مرحلہ یہ ہے کہ
- عوامی ماحول میں حلال و حرام کے فرق کا احساس و شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ حرام کی نحوستوں بالخصوص سود کی بے برکتی اور لعنت و نحوست کو اجاگر کیا جائے۔
- معاشرے میں نجی و سرکاری سطح پر رائج سود کی مختلف صورتوں کو سامنے لایا جائے اور ان سے بچنے کے لیے متبادل طریقوں کے متعلق آگاہی کا ماحول پیدا کیا جائے۔
- علماء کرام، تاجر راہنماؤں اور وکلاء برادری کے درمیان اس سلسلہ میں رابطوں، ملاقاتوں، مشترکہ اجتماعات اور اشتراک عمل کا ماحول قائم کیا جائے، اور
- وفاقی شرعی عدالت میں سودی نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے راہنماؤں اور وکلاء کو سیاسی، اخلاقی اور علمی مدد فراہم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازیں، آمین۔
تعلیمی نظام اور تحریکی تقاضے
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(۱٠ دسمبر ۲۰۲۰ء کو جامعہ فریدیہ اسلام آباد میں اساتذہ و طلبہ کے اجتماع سے خطاب کا خلاصہ )
بعد
الحمد والصلوٰۃ۔ کافی عرصہ کے بعد جامعہ فریدیہ میں حاضری اور اساتذہ و
طلبہ کے ساتھ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ
گزارشات بھی کروں اس لیے تعمیل حکم میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جامعہ
فریدیہ ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں سے ہے اور مختلف حوالوں سے اپنی ایک
الگ تاریخ رکھتا ہے۔ حضرت مولانا محمد عبد اللہ شہیدؒ کی محنتوں کا ثمرہ
اور ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ انہوں نے اور ان کے خاندان و رفقاء نے اس علمی
ادارہ اور مرکز کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور جامعہ فریدیہ آزمائشوں
کے مختلف مراحل سے گزرا ہے۔
اس پس منظر میں مجھے یہ دیکھ کر خوشی
ہوئی ہے کہ یہاں کا تعلیمی تسلسل جاری ہے۔ طلبہ کی بڑی تعداد اور اساتذہ کی
اکثریت بحرانی کیفیات سے دوچار ہونے کے باوجود مصروف تعلیم ہے، جبکہ میری
طالب علمانہ رائے میں تعلیمی تسلسل کو قائم رکھنا اور نظام کو ڈسٹرب ہونے
سے بچانا آج کے دور میں دینی مدارس کے لیے بڑی کامیابی کی حیثیت رکھتا ہے۔
اس لیے کہ جن لوگوں اور طبقوں کو دینی مدارس کے نظام کی بقا مسلسل پریشان
کر رہی ہے ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ان مدارس کا نظام و ماحول کسی نہ کسی
طرح ڈسٹرب ہو جائے اور تعلیمی و معاشرتی کردار ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ ان
حالات میں ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے تعلیمی نظام اور ماحول کو کسی
حالت میں معطل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ آپ حضرات نے گزشتہ کچھ عرصہ کے حالات
میں تعلیمی سلسلہ کو جس صبر و حوصلہ اور حکمت کے ساتھ قائم رکھنے میں
کامیابی حاصل کی ہے اس پر مبارکباد دیتے ہوئے اس سلسلہ میں کردار ادا کرنے
والے سب احباب خصوصاً اسلام آباد کے اکابر علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اس
موقع پر ایک تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ میرے والد
محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدرؒ اور عم مکرم حضرت مولانا صوفی عبد
الحمید خان سواتیؒ ۱۹۴۱ اور ۱۹۴۲ کے دوران دارالعلوم دیوبند جا کر دورۂ
حدیث میں شریک ہوئے تھے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
اور دیگر اکابر اساتذہ سے استفادہ کیا تھا۔ حضرت مدنیؒ تحریک آزادی کے بڑے
راہنماؤں میں سے تھے، اس حوالہ سے وہ گرفتار کر لیے گئے جس پر دارالعلوم
دیوبند کے طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا اور احتجاجی
جلسوں اور جلوسوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو اس حد تک بڑھ گیا کہ تعلیمی نظام
معطل ہو کر رہ گیا حتٰی کہ اس سال سالانہ امتحانات بھی نہیں ہو سکے تھے۔
طلبہ کی اس تحریک کی قیادت کے لیے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ
طلبہ کی جو کمیٹی منتخب کی گئی اس کا سربراہ والد گرامی حضرت مولانا محمد
سرفراز خان صفدرؒ کو بنایا گیا اور انہوں نے کمیٹی کے دیگر ارکان کے ہمراہ
احتجاجی تحریک کی قیادت کی تھی۔ اس تحریک کی مختلف باتیں بیان کرتے ہوئے
والد گرامیؒ نے یہ بات بتائی بلکہ اپنی یادداشتوں میں تحریر بھی فرمائی ہے
کہ انہیں بزرگ اساتذہ اور علماء کرام مسلسل سمجھاتے تھے کہ احتجاج کا حق
ضرور استعمال کرو لیکن اس سے تعلیمی سلسلہ اور مدرسہ کے ماحول کو متاثر نہ
ہونے دو۔ انہیں اس خدشہ سے بھی آگاہ کیا گیا کہ اس طرح انگریزی حکومت کو
دارالعلوم دیوبند کو بند کرنے کا بہانہ ملے گا اور یہ بہت بڑا قومی نقصان
ہو گا۔ والد محترمؒ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بات ہم پر اثرانداز نہیں
ہو رہی تھی اور ہم اپنے جذبات میں مگن احتجاجی تحریک کو پورے جوش و خروش کے
ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے۔ بالآخر جمعیۃ علماء ہند کے سربراہ مفتی اعظم
حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ اور جنرل سیکرٹری حضرت مولانا احمد
سعید دہلویؒ دیوبند تشریف لائے اور کئی ملاقاتوں میں ہمیں اس بات پر قائل
کیا کہ ہم تعلیمی بائیکاٹ اور احتجاجی جلوسوں کا سلسلہ ختم کر دیں۔ اس
حوالہ سے ہمیں ان بزرگوں نے بھی یہ فرمایا کہ احتجاج اور تحریک سے
دارالعلوم دیوبند کے نظام کو ڈسٹرب نہ ہونے دو اور حکمرانوں کے لیے اس بات
کا موقع اور بہانہ فراہم نہ کرو کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف کوئی
کارروائی کر سکیں۔ حضرت والد محترمؒ فرماتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھانے کی
ہر بزرگ نے کوشش کی کہ مدرسہ کو مدرسہ رہنے دو مورچہ میں تبدیل نہ کرو اس
سے نقصان ہو گا اور یہ بات امت کے فائدہ کی نہیں ہے۔ چنانچہ ان بزرگوں کے
حکم اور اصرار پر ہم نے اپنی تحریک روک دی مگر حالات اس حد تک بگڑ چکے تھے
کہ اس سال دارالعلوم کے سالانہ امتحانات نہ ہو سکے اور ہمیں اگلے سال
دوبارہ جا کر امتحانات میں شریک ہونا پڑا۔
اس لیے مجھے جامعہ فریدیہ
کے گزشتہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمی نظام کے بحال ہونے اور اساتذہ و
طلبہ کے ذوق و شوق کا سلسلہ جاری رہنے پر فی الواقع بہت خوشی ہو رہی ہے۔
اس کے ساتھ ایک بات دینی تحریکات اور جدوجہد کے بارے میں بھی عرض کرنا
چاہتا ہوں۔ میں خود تحریکی دنیا کا آدمی ہوں، درجنوں دینی و قومی تحریکات
میں نصف صدی کا عرصہ گزار چکا ہوں اور اپنے تجربات کی روشنی میں گزارش کر
رہا ہوں کہ مسائل تو کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بہت سے مسائل
ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حوالہ سے جدوجہد کرنے کو جی چاہتا ہے اور یہ ہماری
ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ سامنے آنے اور اس میں حصہ لینے کو
جی چاہے یا ضروری ہو تو اس کے لیے تین چار امور کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔
- پہلے نمبر پر یہ کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب تک اصل
ضروریات اور تقاضے سامنے نہ ہوں ہم اپنا کردار صحیح طور پر متعین نہیں کر
سکتے۔
- دوسرے نمبر پر یہ کہ معروضی حالات میں عملاً کیا ہو سکتا
ہے؟ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو ہونا چاہیے وہ ہو بھی جائے، چنانچہ ہم
یہ ہونا چاہیے کے چکر میں جو ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے۔
- تیسرے نمبر پر یہ کہ جو ہو سکتا ہے میں اس کے دائرے میں کیا کر سکتا ہوں؟
اس لیے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو ہو سکتا ہے وہ سب کچھ میں بھی کر سکتا
ہوں۔ اس لیے اپنا کردار طے کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہو گا کہ جو ہو سکتا ہے
اس میں وہ کیا کام ہے جو میرے بس میں ہے۔
- جبکہ چوتھے نمبر پر یہ
دیکھنا ضروری ہے کہ میں جو کچھ کروں گا اس سے وہ کام تو ڈسٹرب نہیں ہو جائے
گا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ کسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے اب تک ہونے والے
کام کو داؤ پر لگا دینا کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے۔ اصل دانش و حکمت یہ
ہے کہ جو موجود ہے اسے باقی اور محفوظ رکھتے ہوئے جو ہو سکتا ہے اسے کرنے
کی کوشش کی جائے۔
جامعہ فریدیہ کے حوالہ سے تعلیمی اور تحریکی دونوں
قسم کے سوال سامنے آتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں کے بارے میں مختصرًا کچھ
گزارشات پیش کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ جامعہ فریدیہ سمیت ہمارے تمام دینی
مدارس، مراکز اور اداروں کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں ان کی ضروریات اور
تقاضوں کے مطابق صحیح محنت کی توفیق سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔
حورانِ بہشتی کے قرآنی اوصاف وخصائل
اور خواتین کے لیے ترغیب اور دلچسپی کے پہلو
مولانا محمد عبد اللہ شارق
”حورانِ بہشتی“کا مصداق
حورانِ بہشتی“ کا تذکرہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، قرآن وحدیث میں اِن کے حسن وجمال، پرکشش اوصاف،عمدہ خصائل اور جاذبیتِ نظر کے کئی قصے بیان ہوئے ہیں۔ قرآنِ مجید میں اللہ تبارک وتعالی جہاں کہیں بھی جنت کی خوابوں جیسی زندگی کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہاں پر بہت دفعہ اِن حوروں کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ حوروں کے اِس تذکرہ میں مردوں اور عورتوں، دونوں کے لیے یکساں رغبت کا سامان موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ تصور کررکھا ہے کہ شاید اِن کا تذکرہ صرف مردوں کو راغب کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مومن عورتوں کے لیے یہ آیات واحادیث غیرمتعلقہ ہیں۔ یہیں سے پھر خواتین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت کے اندر مومن مردوں کو حوریں ملیں گی تو مومن عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور ان کو جو کچھ بھی ملے گا تو اس کا تذکرہ حوروں کی طرح قرآن وحدیث میں بار بار کیوں نہیں ہے؟جنت کی باقی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن مذکورہ غلط فہمی کی وجہ سے حورانِ بہشتی کے حسن وجمال کے تذکرے خواتین کے لیے بے لذت اور غیر متعلقہ ہوکر رہ گئے ہیں کیونکہ بقول ان کے اِن تذکروں میں کسی مرد کو ہی دلچسپی ہوسکتی ہے، کسی عورت کو نہیں۔ جو خواتین اس غلط فہمی کو زبان پر نہیں لاپاتیں، وہ بھی اِن آیات واحادیث کو دل ہی دل میں بہرحال یوں بے تاثر ہوکر سنتی ہیں کہ گویا اِن میں خواتین کے لیےشوق اور رغبت کا کوئی سامان نہیں، یہ محض مردوں کی ترغیب کے لیے ہیں اور جنت کی اِس نعمت کے بارہ میں بتلا کر بس انہی میں دلچسپی وشوق مندی پیدا کرنا مقصود ہے۔
اِن غلط فہمیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے ”حورانِ بہشتی“ کو ایک ماورائی مخلوق سمجھ لیا ہے جو نہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نہ ہی اِس دنیا سے کبھی ان کا کوئی تعلق رہا ہے۔ بے شک یہ بات درست ہے کہ جنت میں رنگ اور رونق بکھیرنے والی حسینائیں اپنے دیو مالائی حسن اور غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے اس دنیا کی حسیناؤں سے بالکل مختلف ہوں گی، بلکہ یہ بات بھی درست ہے کہ وہ سب کی سب دنیا سے گذر کر جانے والی نہیں ہوں گی اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جنہیں رب العلمین نے کلمہء ”کن“ کے ساتھ کسی اور طریقہ سے وجود بخشا ہوگا اور بنا کسی دنیاوی عبادت وریاضت اور جہد ومشقت کے محض اپنے فضل واحسان سے جنت کے خوابوں جیسے مسکن کی زینت بنایا ہوگا۔ بے شک یہ بات درست ہے اور صرف عورتوں کے حق میں نہیں، بلکہ ایک صحیح السند حدیث کی رو سے کچھ مرد بھی شاید ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر کلمہء کن سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
”لاتزال جھنم تلقی فيھا وتقول ھل من مزيد حتی يضع رب العزۃ فيھا قدمہ فينزوي بعضھا إلی بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنۃ فضل حتی ينشئ اللہ لھا خلقا فيسكنھم فضل الجنۃ“ (صحیح مسلم۔ رقم 2848)
یعنی ”جہنم تمام تر بھرتی ہونے کے باوجود ”کچھ اور“ کا تقاضا کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اس پر اپنا قدم رکھیں گے اور وہ سکڑ کر ”بس بس“ کرنے لگے گی، جبکہ اسی طرح جنت بھی تمام تر بھرتی کے باوجود باقی بچ رہے گی اور اللہ جل شانہ (”کلمہ ”کن“ کے ساتھ) کچھ مخلوق پیدا کرکے اسے بچ رہنے والی جنت میں بسادیں گے۔“
قرآن وحدیث میں موجود قرائن سے محسوس ہوتا ہے کہ جنتی حسیناؤں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہی ہوگی اور یہ بھی درست ہے کہ حورانِ بہشتی کا ایک بڑا مصداق یہی حسینائیں ہیں، مگر یہ سمجھنا کہ قرآن وحدیث میں جہاں جہاں حورانِ بہشتی کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد بس یہی خاص طور پر پیدا کی گئی حسینائیں ہوتی ہیں، ہمارے خیال میں سراسر ایک غلط فہمی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اِس کے برعکس لغت، قرآن اوراحادیث وآثار کے سارے قرائن اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں بنیادی طور پر حورانِ بہشتی کا مصداق وہ سب حسینائیں ہیں جو جنت میں بسائی جائیں گی، خواہ وہ کلمہء کن سے پیدا کی گئی ہوں یا دنیا کی اہلِ ایمان خواتین ہوں۔
تاہم آگے بڑھنے سے قبل ایک نہایت ضروری تمہید کو سمجھ لینا چاہئےکہ دنیا سے گذرکر جانے والی مومن خواتین کے دخولِ جنت کا کوئی منکر نہیں، امت کا اتفاق ہے کہ یہ جنت ہی میں جائیں گی۔ غلط فہمی صرف یہ سمجھنے میں واقع ہوئی ہے کہ قرآن وحدیث میں اکثر وبیشتر جن جنتی حسیناؤں کا تذکرہ آتا ہے تو ان سے مراد صرف کلمہء ”کن“ سے پیدا ہونے والی حسینائیں ہوتی ہیں اور لفظِ ”حور“ کا مصداق بھی صرف یہی ہوتی ہیں۔ غلط فہمی صرف اتنی ہی ہے اور گو بہت بڑی نہیں، مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب قرآن وحدیث میں مذکور حورانِ بہشتی کے ولولہ خیز تذکرے ہماری خواتین سے بے تعلق ہوجاتے ہیں کیونکہ کلمہء کن سے پیدا ہونے والی حورانِ بہشتی میں دلچسپی کسی مرد کو ہی ہوسکتی ہے۔ غلط فہمی پر مبنی یہ قول چونکہ بعض کتبِ تفسیر میں مذکور ہے، بعض نے اس کو ترجیح بھی دیا ہے اور پھر یہ امت میں مشہور بھی ہے تو اس لیے یہ غلط فہمی تناور ہوکر ایک درخت بن چکی ہے۔ زیرِ نظر تحریر میں اسی غلط فہمی کا علمی جائزہ لینا مقصود ہے اور اس وضاحت کے ساتھ کہ خود ماضی ہی کے بعض مفسرین نے اسے ایک غلط فہمی قرار دیا ہے۔
”حور“ کا لغوی مفہوم
سب سے پہلے ”حور“ کے لغوی اطلاق کو لیجئے، یہ لفظ ”حوراء“کی جمع ہے اور ”اسمِ صفت“ ہے، اسمِ جنس نہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ”حور“ کا لفظ عربی زبان میں انسان، جن اور فرشتہ کی طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے کوئی خاص نوع یا جنس کی مخلوق مراد لی جاتی ہو،بلکہ یہ لفظ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو خوب صورت، دراز قد اور صاحبِ کردار کہہ دیا جائے۔ چنانچہ اسلام کی آمد سے قبل بھی ”حور“ کا لفظ ”حسینہ“ کے معنوں میں عربوں کے ہاں مستعمل اور مروج تھا اور اُن عربوں کے ہاں مستعمل تھا جو سرے سے کسی جنت نامی چیز کو ہی نہیں مانتے تھے۔ عموما ان کی بدوی عورتیں شہری عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کرتی تھیں۔ لسان العرب اورتاج العروس وغیرہ (کتبِ لغت) کی عبارات کے ساتھ ساتھ امام مجاہد کے ایک تفسیری قول کو ملانے سے ہماری نظر میں ”حور“ کے مکمل معنی کچھ یوں بنتے ہیں: وہ لڑکیاں جو گوری ہوں اور جن کی آنکھوں کی جھلمل اتنی بے داغ اور پرکشش ہو کہ دیکھنے والے کی نگاہ ان آنکھوں کی تاب نہ لاسکے۔ گویا مختصر لفظوں میں ہم ”حور“ کا ترجمہ ”جادو نظر حسینائیں“ کرسکتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن وحدیث میں کہیں کہیں جنتی حسیناؤں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جنت میں دیگر نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ ”حوریں“ بھی ہوں گی تو یہاں پر اس لفظ کو اسمِ جنس بنا دینا اور بغیر کسی قرینہ کے یہ کہنا کہ اس سے مراد صرف وہ خواتین ہیں جنہیں خدا تعالی بغیر کسی دنیاوی عبادت وریاضت کے جنت عطا فرمائیں گے، کیوں کر درست ہوسکتا ہے؟جب عربی زبان میں اس کے معنی مطلق ”حسینائیں“ ہیں تو قرآن وحدیث میں بھی اس لفظ کا اطلاق اسی مفہوم میں ہونا چاہئے اور ”حورانِ بہشتی“ کے اطلاق میں وہ سب حسینائیں شامل ہونی چاہئیں جنہیں پروردگار جنت کی زینت پنائے گا خواہ وہ دنیا میں آدم زاد بھی رہی ہوں یا نہ۔ چنانچہ طبری اور ابنِ کثیر نے لفظِ ”حور“ کا صرف لغوی مفہوم واضح کرنے پر اکتفاء کیا ہے اور یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ طبری اور ابنِ کثیر کسی تخصیص کے قائل نہیں کیونکہ اس لفظ کا لغوی اطلاق تعمیم کا مقتضی ہے، نہ کہ تخصیص کا۔
یہاں ضمنا یہ بات عرض کردینا بھی مناسب ہوگا کہ فیروزآبادی اور راغب اصفہانی کے بقول ”حور“ کا لفظ عربی زبان میں فی الاصل جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہےاور جمع مذکر کے لیے بھی اور بعض معاصر اہلِ علم کے مطابق ”حور“ کے قرآنی اطلاق میں بھی جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کا مفہوم داخل ہے، یعنی قرآن میں جہاں اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے تو وہاں دونوں کے حسن کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہے۔ زیرِ بحث اعتراضات کا دفعیہ کرنے کے لیے یہ توجیہ بظاہر بہت اچھی محسوس ہوتی ہے، لیکن مفسرین نے عام طور پر قرآن مجید میں وارد لفظِ ”حور“ کی تفسیر صرف حسین عورتوں کے ساتھ ہی کی ہے اور ہماری رائے میں یہی بات درست ہے۔ وجہ یہ کہ قرآن میں اکثر جگہ جنتی حسیناؤں کا ذکر مؤنث کے تصریحی صیغہ کے ساتھ آیا ہے اور وہ چار مقامات جہاں ”حور“ کا لفظ آیا ہے تو ان میں سے بھی دو مقامات (الرحمن، الواقعہ) کے سیاق وسباق میں مؤنث ہی کا اسلوب چل رہا ہے اور ممکن ہی نہیں کہ وہاں اسے جمع مؤنث کے ساتھ ساتھ جمع مذکر بھی قرار دیا جائے۔ ان مقامات کی تفصیل اگلے عنوان کے تحت مذکور ہے۔
قرآنی قرائن
”حور“ کا لغوی مفہوم جان لینے کے بعد خود قرآنِ مجید کے داخلی قرائن پر غور کیجئے، قرآن میں اکثر جگہوں پر جنتی حسیناؤں کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ وہاں ”حور“ کا لفظ سرے سے استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ مختلف الفاظ میں بس ان حسیناؤں کی سیرت وصورت، حسن ورعنائی، وجاہت وکشش اور پاکیزگی کو بیان کیا گیاہے۔ ذرا سوچئے کہ کیا اِس کے بعد بھی جنتی حسیناؤں کے اِن اوصاف وخصائل کو کلمہء ”کن“ سے پیدا ہونے والی حسیناؤں سے مخصوص کرنے کا کوئی جواز ہے؟ ہماری تحقیق کے مطابق قرآنِ مجید میں صرف چار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالی نے ان حسیناؤں کے لیے ”حور“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور ان کے حوالہ جات یہ ہیں: ۱۔ ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاھُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ (الدخان: 54) ۔ ۲۔ ﴿وَزَوَّجْنَاھُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ (الطور: 20)۔ ۳۔ ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ (الرحمن: 72)۔ ۴۔ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ (الواقعہ: 22)
جبکہ تقریبا دس مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اِن حسیناؤں کا ذکر ہوا ہے مگر وہاں حور کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ دیکھئے: ۱۔ ﴿وَلَھُمْ فِيھَا أَزْوَاجٌ مُّطَھَّرَۃ﴾ (البقرہ: 25)۔ ۲۔ ﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَھَّرَۃ﴾ (آلِ عمران: 15)۔ ۳۔ ﴿لَّھُمْ فِيھَا أَزْوَاجٌ مُّطَھَّرَۃ﴾ (النساء: 57)۔ ۴۔ ﴿ھُمْ وَأَزْوَاجُھُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَی الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ﴾ (یس: 56)۔ ۵۔ ﴿وَعِنْدَھُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾ (الصافات: 48)۔۶۔ ﴿وَعِندَھُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ﴾ (ص: 52)۔ ۷۔ ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّۃَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ (الزخرف: 70)۔ ۸۔ ﴿فِيھِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْھُنَّ إِنسٌ قَبْلَھُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ (الرحمن: 56)۔ ۹۔ ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاھُنَّ إِنشَاء º فَجَعَلْنَاھُنَّ أَبْكَارًا º عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ (الواقعہ: 35)۔ 10۔ ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ (النباء: 33)
احادیث وآثار
اس کے بعد اگر احادیث وآثار کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی کم از کم ہمیں تو ایسا کوئی قرینہ نظر نہیں آیا جس سے محسوس ہو کہ حورانِ بہشتی کا اطلاق صرف کلمہء ”کن“ سے پیدا ہونے والی حسیناؤں پر ہوتا ہے اور جنتی حسیناؤں کے تذکروں میں صرف وہی شامل ہیں یا یہ کہ یہ تذکرے صرف مردوں کی دلچسپی کے لیے ہیں۔ یوں تو قرینہء تخصیص کی ناموجودگی بذاتِ خود عدمِ تخصیص کی ایک دلیل ہے، لیکن یہاں پر کچھ ایسے قرینے ملتے ہیں جن سے الٹا اس تصورِ تخصیص کی نفی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا
(1)قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاھُنَّ إِنشَاء º فَجَعَلْنَاھُنَّ أَبْكَارًا﴾ (الواقعہ: 35، 36) یعنی ”ہم ان حسیناؤں کو ایک خاص طرز سے وجود بخشیں گے اور انہیں دوشیزگی عطا کریں گے……“ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صریح ارشاد صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ دنیا کے اندر جو مومن بیبیاں بوڑھی اور سن رسیدہ ہوجائیں گی، مذکورہ آیت کی رو سے اللہ تعالی انہیں بھی جنت کے اندر نئے سرے سے جوانی اور دوشیزگی عطا کریں گے۔ دیکھئے:
أتت عجوز إِلَی النَّبِيِّ صَلَّی اللَّہُ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّہِ، ادْعُ اللَّہَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّۃَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلاَنٍ، إِنَّ الْجَنَّۃَ لاَ تَدْخُلُھَا عَجُوزٌ قَالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي فَقَالَ: أَخْبِرُوھَا أَنَّھَا لاَ تَدْخُلُھَا وَھِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّہَ تَعَالَی يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاھُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاھُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ (شمائل الترمذي، رقم 241۔جامع الترمذی، رقم 3296۔ البانی نے پہلی سند کو حسن قرار دیا ہے۔)
یعنی ”ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں پہنچا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بی بی! جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی۔ راوی بتلاتے ہیں کہ یہ سن کر وہ بڑھیا روتے ہوئے واپس پھر نے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتلاؤ: جنت میں بڑھیا بڑھاپا لے کر نہیں جائے گی (بلکہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہوکر جائے گا) کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: ”ہم انہیں ایک نیا جنم دے کر کنواریاں، اپنے خاوندوں کی لاڈلیاں اور عمر میں یکساں بنادیں گے۔“
(2) اسی طرح ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو بکرؓ کی اہلیہ حضرت ام رومانؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا: ”من سرہ أن ينظر إلی امرأۃ من الحور العين فلينظر إلی أم رومان“ (الطبقات الكبرى ، ابن سعد، 8/276) یعنی ”جو آدمی کسی حور کو دیکھنا پسند کرے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔“ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں ام رومانؓ کے جنتی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان پر ”حور“ کا اطلاق کیا۔
(3) ایک روایت میں صحابیء رسول ابو نحیلہؓ کی ایک دعاء نقل کی گئی ہے کہ ”اللھم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين“ (المعجم الكبير للطبراني، ۲۲/ 278) یعنی ”اے پروردگار مجھے اپنا مقرب بنا اور میری ماں کو حورانِ بہشتی میں شامل فرما۔“
(4)حسن بصری رحمہ اللہ نے نو صحابہ کرام سے یہ فیصلہ کن مضمون نقل کیا ہے کہ ”حور“ سے مراد کوئی اور ہو نہ ہو، مومن عورتیں تو ہیں ہی اور اس روایت کی سند بھی موجود ہے۔ دیکھئے:
”عبد الرزاق قال: أنا جعفر بن سليمان عن عباد بن عمرو قال: سأل يزيد ابن أبي مريم الحسن فقال: يا أبا سعيد ما الحور العين؟ قال عجائزكم ھؤلاء الدرد ينشئھن اللہ خلقا آخر، فقال لہ يزيد بن أبي مريم: عن من تذكر ھذا يا أبا سعيد، قال: فحسر الحسن عن ذراعيہ ثم قال: حدثني فلان وفلان حتی عد من المھاجرين خمسۃ وعد من الأنصار أربعۃ. عبد الرزاق قال أنا معمر عمن سمع الحسن يقول حور العين من نساء الدنيا ينشئھن اللہ خلقا آخر“ (تفسیر الصنعانی، سورہ الدخان: 54)
یعنی ”عبد الرزاق نے جعفر اور جعفر نے عباد بن عمرو سے نقل کیا ہے کہ یزید بن ابی مریم نے حسن بصری سے پوچھا کہ حوریں کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی تمہاری بوڑھیاں جن کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، اللہ انہیں ایک نئی تخلیق عطا کرے گا۔ یزید نے جب دریافت کیا کہ یہ آپ نے کس سے سنا؟ تو یہ سن کر حسن نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور گن گن کر نام بتانے لگے، ان میں پانچ نام مہاجرین کے اور چار انصاریوں کے تھے۔ یہی تفسیر حسن بصری سے ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔“
(5) نیز اگر حورانِ بہشتی کے تذکرے صرف مردوں کا شوقِ جنت بڑھانے کے لیے ہوتے اور عورتوں سے غیر متعلق ہوتے تو اس کی وجہ سے جو ابہامات ہماری خواتین کو لاحق ہوتے ہیں،بعینہ یہی ابہامات عہدِ نبوی کی خواتین کے ذہن میں بھی ضرور پیدا ہوتے اور وہ اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتیں۔ عہدِ نبوی کی تاریخ گواہ ہے کہ عہدِ نبوی کی خواتین کو سوال اٹھانے کی مکمل آزادی حاصل تھی اور وہ اس طرح کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاجھجک پوچھ لیا کرتی تھیں۔ ان کے ذہنوں میں ایسا کوئی سوال پیدا نہ ہونا اور احادیث وروایات کے عظیم الشان ذخیرہ کا ایسی کسی قسم کی رویت سے یکسر خالی ہونا بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ عہدِ نبوی کی خواتین لا محالہ ”حورانِ بہشتی“ کے اطلاق میں مومن بیبیوں کو بھی شامل سمجھتی تھیں، ورنہ ان کے ذہن میں بھی یا کم از کم بعد کی کچھ صدیوں کی مومن خواتین کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا۔
مذکورہ تمام قرائن وشواہد گواہی دیتے ہیں کہ دنیا سے گذر کر جانے والی مومن خواتین پر ”حور“ کا اطلاق کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
حورانِ بہشتی کے تذکرہ میں خواتین کے لیے ترغیب کے پہلو
جب یہ بات واضح ہوگئی کہ ”حورانِ بہشتی“ سے مراد علی الاطلاق جنتی حسینائیں ہیں (خواہ وہ دنیا کی مومن عورتیں ہوں یا کلمہء ”کن“ سے پیدا ہونے والی حسینائیں) اور ان حسیناؤں کے بارہ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ زنانہ حسن وجمال کا مرقع بن کر مومن مردوں ہی کے پاس ہوں گی تو اب یہ سوال باقی ہی نہیں رہتا کہ مومن مردوں کے پاس تو ہ کلمہء کن سے پیدا ہونے والی حسینائیں ہوں گی اور حسن وجمال کے بتلائے گئے احوال بھی انہی کے ہیں، لہذا یہ دنیا کی مومن خواتین کہاں جائیں گی اور انہیں کیا ملے گا۔ قرآن وحدیث میں جب حورانِ بہشتی کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں صرف مردوں کو ہی یہ نہیں بتایا جارہا ہوتا کہ انہیں جنت میں دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ حسینائیں بھی ملیں گی، بلکہ مومن خواتین کو بھی گویا یہ پیغام دیا جارہا ہوتا ہے کہ جنت میں آنے والی خواتین کو کس طرح ایک حسین سراپا دے کر جنتی مردوں کی بیگمات بنایا جائے گا۔ پس یہ آیات واحادیث صرف مردوں کی ترغیب کے لیے نہیں ہوتیں، بلکہ خواتین کے لیے بھی اِن میں دلچسپی کا پورا پورا سامان موجود ہوتا ہے۔
کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دنیا کی چند روزہ گوری رنگت، باسی ہوجانے والے تیکھے نقوش، خاک سے نکلنے والے سونا چاندی اور چند لمحوں بعد بے رونق ہوجانے والے سرخی پاؤڈر کے لیے صنفِ نازک بے چین رہتی ہے، انہی کے خواب اور انہی کے خیال ہماری خواتین پر طاری رہتے ہیں، انہی کی آرزو کرتے کرتے ہمارا دم نکل جاتا ہے اور ایک وقتی رفاقت کے بعد جس دلہا نے پیوندِ خاک ہوجانا ہے، اس دلہا کی دلہن بننے کے لیے اور جیسے تیسے مردوں کی بیوی بننے کے لیے ہماری کنواریاں دعائیں مانگتی ہیں اور دعائیں مانگتے ہوئے انہیں رونا بھی آتا ہے، پس یہ کیسے ممکن ہے کہ ذرہ سے لے کر آفتاب تک ہر چیز کو وجود بخشنے والا پروردگار جس حسن اور جس سراپا کی تعریف کرے، جس صورت اور سیرت کو بطور ایک مثال کے پیش کرے، جس جمال اور رعنائی سے اپنی جنت کو سجائے اور پھر ایسے حسن وجمال کے پیکروں کو اپنے انعام یافتہ مثالی مردوں کے ساتھ بیاہنے کی بات کرے تو اس افسانوی اور دیو مالائی حسن کو حقیقتا پالینے کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی شوق پیدا نہ ہو اور نہ ہی رب العلمین کے انعام یافتہ مثالی روپ اور مثالی کردار والے مردوں کے ساتھ بیاہنے کو ہمارے دل مچلیں؟
کسی بھی عورت سے معلوم کرلیجئے کہ عموما خواتین کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان کی بات میں نہیں کرتا کہ یہ تو ضروریات ہیں اور بے شک جنت کے اندر یہ بھی اعلی ترین پیمانہ پر پوری ہوں گی۔ میں بات کر رہا ہوں لذتوں کی، خواہشات کی اور تعیشات کی۔ ان کے دائرہ میں رہتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی عورت کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے اولین خواہش جو اسے پریشان کن حد تک لاحق ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح میں ایک مثالی حسن کی مالک بن جاؤں، میری خوب روئی دیو مالائی ہو، میری نگاہیں صنفِ مخالف کو مبہوت کر کے رکھ دیں اور یہ کہ میرا رفیقِ حیات ایک مثالی کردار، مثالی شخصیت اور مثالی ہی روپ کا مالک ہو۔ اب ذرا حورانِ بہشتی والی آیات واحادیث کو پڑھئے، کیا ان میں صنفِ نازک کی انہی چاہتوں کی تکمیل کی بات نہیں ہورہی؟ تو اب آپ خود ہی بتائیے کہ یہ آیات واحادیث عورتوں سے غیر متعلق کیوں کر ہوئیں؟ بے شک ان میں مردوں کے لیے بھی پوری پوری دلچسپی کا سامان موجود ہے، مگریہ عورتوں کے لیے بھی غیر متعلقہ ہرگز نہیں ہیں۔ ہاں، اگر عورتوں کو لازوال حسن، بے مثال سراپا، قابلِ رشک شخصیت، نہ ختم ہونے والی جوانی، نگینہ جیسی صورت اور حسین، خلیق ومعزز رفیق کی خواہش نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں حورانِ بہشتی کے احوال میں واقعی ان کے لیے دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہے۔
جنتی حسیناؤں کے قرآنی اوصاف وخصائل
مناسب محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم ایک مفصل نظر جنتی حسیناؤں کے اوصاف وخصائل پر ڈالیں اور واضح کریں کہ اِن کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ کس کس طرح سے خواتین کے لیے بھی رغبت اور سبق کا پورا پورا سامان موجود ہے ۔ ہم نے یہاں بنیادی طور پر صرف ان اوصاف وخصائل کا انتخاب کیا ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور احادیث میں مذکورتفصیلی اوصاف کو اس ضمن میں کہیں کہیں صرف وضاحت کے لیے لے آئے ہیں:
۱۔ سب سے پہلی خوبی تو وہی ہے جو انہیں ”حور“ کا نام دے کر اللہ نے واضح فرمائی ہے۔ ”حور“ کے معنی ہیں: ”آنکھوں کے اندر طلسماتی کشش رکھنے والی اجلے رنگ کی حسینائیں“، خواتین سوچ لیں کہ کیا انہیں ایسا بننے کا واقعی کوئی شوق نہیں ہے؟
۲۔ ایک اور چیز ان کے بارہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ”عِین“ ہیں (الصافات: 48)، یعنی ”بڑی بڑی آنکھوں والی آہو چشم حسینائیں۔“
۳۔ ایک خصوصیت یہ بھی بتلائی گئی کہ دنیا کے اندر اگر وہ سن رسیدہ بوڑھیاں بھی تھیں تو جنت کے اندر اللہ جل شانہ انہیں پھر سےبھرپور شباب کے ساتھ کنواریاں بنا کر اٹھائیں گے(الواقعہ: 63) اور یوں ہوجائیں گی کہ گویا کبھی ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ (الرحمن: 65) وقت گذرنے کے ساتھ وہ مضمحل نہیں ہوں گی، بلکہ کنواریاں ہوں گی، کنواریاں رہیں گی اور کنواریوں جیسی رعنائی، کنواریوں جیسی تازگی، کنورایوں جیسی اٹھان، کنواریوں جیسے جذبے اور کنواریوں جیسی شفافیت گویا ہمیشہ برقرار رہے گی۔
۴۔ اگر کسی بہت ہی خوب صورت سراپے پر انسان کی نظر پڑے تو یوں گمان ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی نگینہ دیکھ لیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حورانِ بہشتی کے بارہ میں بھی ان کے اجلے اور دُھلے ہوئے حسن کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ گویا وہ کوئی داغ دھبوں سے دور، پردوں میں پڑا ہوا صاف وشفاف موتی ہیں۔ (الواقعہ: 23)
۵۔ ان حسیناؤں کا سراپا ایسا سرخ وسفید ہوگا اور ایسی بیش قیمت پوشاکیں انہوں نے پہن رکھی ہوں گی کہ ان پہ یاقوت ومرجان اور رنگ برنگی موتیوں کا گمان ہوگا(الرحمن: 58) اور ان کا بے داغ وجود گویا چھلکے میں چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہے جو ابال کر چھیلنے سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا گول مٹول وجود آنکھوں کو لذت وفرحت بخشتا ہے۔(الصافات: 49)
۶۔ وہ ”کواعب“ ہوں گی (النباء: 33)، یعنی ان کی چھاتیوں پر جوانی کے دلکش ابھاروں کی گولائی ایک متناسب اٹھان کے ساتھ ظاہر ہوگی جیساکہ ابتدائے بلوغت میں ہوتا ہے۔ (دیکھئے؛ روح المعانی) ایسی صفات کے بارہ میں کچھ کہتے سنتے ہوئے، ممکن ہے کہ ہم شرمائیں، لیکن کیا اس بات میں کوئی شک ہوسکتاہے کہ مرد عورتوں کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور عورتیں خود اپنے آپ کوبھی؟
۷۔ وہ ”خیرات حسان“ یعنی ”ملکہ حسن“ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق اور خوش اطور بھی ہوں گی۔ (الرحمن: 70)
۸۔ ایک صفت ان کی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ”عُرُب“ ہوں گی (الواقعہ: 37) جس کے معنی عربی لغت کی رو سے کچھ یوں کیے جاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو اپنے مردوں کی محبوب ہوں، ناز وانداز کے سارے اسلوب جانتی ہوں، ان کی اداؤں میں ایک گرمجوشی اور دلربائی ہو، اپنے مردوں پر خود بھی فدا ہوں، ہنسنے اور ہنسانے والی ہوں، شیریں گفتار ہوں اور اپنے مردوں کی لاڈلی ہوں، بالفاظِ دیگر نسوانی خوبیوں کا ایک خوب صورت مرقع ہوں۔ اردومیں اس کا ترجمہ ”لاڈلی ومحبوب“ بھی گویا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں دل اٹکانے کے سارے قرینے ضمنا آجاتے ہیں۔ قرآنی بیان کی رو سے حورانِ بہشتی گویا دل اٹکانے کے قرینوں میں محاورتا نہیں، بلکہ حقیقتا طاق ہوں گی۔
۹۔ اپنے رفیقوں کی ہم عمر ہوں گی۔ (ص: 52)
۰۱۔ وہ ”مطہرۃ“ یعنی ”غلاظتوں اور نجاستوں سے پاک“ ہوں گی۔ (البقرہ: 25) واقفانِ حال جانتے ہیں کہ ماہواری کے ایام عورت کے لیے کتنی کوفت کے ایام ہوتے ہیں، جبکہ جنت کے بارہ میں یہ بتایا جارہا ہے کہ وہاں اس کوفت کا نام ونشان بھی نہیں ہوگا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے ماہواری تو در کنار، وہاں بول وبراز کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ (تفسیر ابنِ کثیر)
۱۱۔ ایک بات جو تقریبا ہر جگہ کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حسینائیں جنتی مردوں کے پاس ہوں گی اور ان کی زوجیت میں ہمیشہ رہیں گی۔
۲۱۔ وہ ”مقصورات فی الخیام“ ہوں گی، یعنی اپنے مردوں کی نظر میں بازار کا شوپیس بنانے کی نہیں، بلکہ ایک قابلِ حفاظت اور سنبھال کر رکھے جانے کی چیز ہوں گی اور ”پردہ نشین“ ہوں گی۔ (الرحمن: 72) حورانِ بہشتی کی اس خصلت میں ہر باحیاء عورت کے لیے سامانِ رغبت کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی ہے، سبق یہ کہ جن بیبیوں نے جنت میں جا کر حیاء کے قرینوں کو مد نظر رکھنا ہے، کیا دنیا کے اندر وہ بے حیاء ہوکر گلیوں اور بازاروں میں اپنے حسن کو نیلام کریں گی؟ باقی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر قیدی بن کر رہیں گی اور نہ ہی یہ کہ دنیا میں جنتی عورتوں کو گھر کا قیدی بن کر رہنے کا حکم ہے، نہیں! بلکہ یہ کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گی باپردہ ہوں گی، غیر مردوں کی نگاہوں سے مستور ہوں گی اور اپنے شوہروں میں ہی عزت، لذت اور راحت کے سارے سامان مجتمع پائیں گی۔
23۔ ایک صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ ”قاصرات الطرف“ ہوں گی۔ اس کے دو معنی ہوسکتے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ اول یہ کہ اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی، یعنی جنت میں خدا تعالی ہر ایک مرد کو ایسا حسن عطا فرمائیں گے، متعلقہ تمام حوروں کے لیے اپنے اپنے شوہر اتنے حسین کردیے جائیں گے اور ہر ایک حسینہ کا اپنے اپنے مرد سے متعلق تاثر اتنا قوی ہوگا کہ نگاہ کسی اور طرف موڑنے کو سرے سے جی ہی نہیں چاہے گا، چنانچہ ایک روایت کے مطابق وہ اپنے شوہر سے کہے گی: ”وعزّۃ ربي وجلالہ وجمالہ، إن أری في الجنۃ شيئا أحسن منك، فالحمد للہ الذي جعلك زوجي، وجعلني زوجَك“ (تفسیر ابنِ جریر، الرحمن: 56) یعنی ”مجھے اپنے رب کی عزت، عظمت اور جمال کی قسم، جنت میں تم سے زیادہ حسین چیز مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی، شکر ہے اس رب کا جس نے تجھ کو میرا اور مجھ کو تیرا رفیق بنایا۔“
یہ ”قاصرات الطرف“ کی ایک تفسیر ہے اور عربی محاورہ کی رو سے درست ہے، جبکہ ایک دوسری تفسیر کے مطابق ”قاصرات الطرف“ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کی نگاہ کو اِدھر اُدھر نہیں ہونے دیں گی، گویا ان کے سراپا میں ایسی بجلیاں بھری ہوں گی جو دیکھنے والے کی نگاہ کو جکڑ لیں گی اور اِدھر اُدھر کا ہوش نہیں رہنے دیں گی اور ہر عورت اپنے خاوند کے لیے ایسی ہی ہوگی۔ ”قاصرات الطرف“ کا یہ معنی بھی عربی محاورہ کی رو سے درست ہے اور بعض مفسرین نے اسے اختیار کیا ہے۔ (دیکھئے: روح المعانی) سو یہ لفظ اپنی ایک تفسیر کی رو سے عورت کے حسن کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے دیکھنے والے کی نگاہوں کو جکڑ لیں گی اور ادھر ادھر کا ہوش نہیں رہنے دیں گی، جبکہ دوسری تفسیر کی رو سے خاوند کے حسن کو بیان کرتا ہے کہ وہ ان کے سوا کسی کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گی۔ قرآن میں اس جگہ ایک قطعی الدلالہ لفظ استعمال فرمانے کی بجائے ظنی الدلالہ یا یوں کہیں کہ ذو معنی لفظ استعمال فر ما کر گویا دونوں کے غیر معمولی حسن کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔
حورانِ بہشتی کے مذکورہ اوصاف کے اندر خواتین غور کریں اور پھر سوچیں کہ کیا یہ اوصاف وخصائل ان سے غیر متعلقہ ہیں اور اِن میں اُن کے لیے کیا واقعی کوئی سبق اور کوئی رغبت نہیں ہے اور کیا ان اوصاف میں صرف مردوں کو رغبت ہوتی ہے یا پھر عورت بھی خود کو ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہے؟
جنتی مردوں کا حسن وجمال
ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوسکتا ہے کہ قرآن وحدیث میں چلئے، جنتی حسیناؤں کے اوصاف وخصائل تو موجود ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ ان میں خواتین کو بھی رغبت ہونی چاہئے، لیکن سوال یہ ہے کہ خود ان مردوں کے حسن وجمال کا کوئی تذکرہ کیوں نہیں ہے جنہوں نے عورتوں کا رفیق بننا ہے؟ اس کے جواب میں پہلی گذارش تو یہ ہے کہ ”قاصرات الطرف“ کا پہلا مفہوم جو ابھی بیان ہوا، وہ در اصل جنتی مردوں ہی کے حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے، چنانچہ متعلقہ ایک روایت بھی ابھی بیان ہوئی ہے جس میں جنتی عورت اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہے۔ نیز ایک اور روایت کی رو سے جنتی مردوں کی آنکھیں سرمگیں ہوں گی، سراپا بالوں کے بغیر ہوگا اور چہرہ پر ڈاڑھیاں نہیں ہوں گی۔ (جامع الترمذی، رقم 2359) نیز ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کے اندر ایک بازار ہوگا، اس بازار میں عورتوں اور مردوں کی تصویریں لگی ہوں گی، انسان کو جو تصویر اچھی لگے گی اس میں داخل ہوگا اور ویسا ہی سراپا لے کر باہر آجائے گا۔ (جامع الترمذی، رقم 2550)
قرآن میں ارشاد ہے کہ وہ ریشم کے بیش قیمت لباس میں ملبوس ہوں گے اور انہوں نے سونا، چاندی و موتیوں کے جڑاؤکنگن پہن رکھے ہوں گے۔ (الحج: 23، الانسان: 21) نیز ان کے چہرے روشن وچمکدار ہوں گے (آلِ عمران: 106) ان کے چہرے کھلتے ہنستے اور بارونق ہوں گے (عبس: 38، 39) اور ان پر ایک بشاشت، تازگی، شگفتگی اور تمتماہٹ دیکھی جاسکے گی۔ (القیامہ: 22) وہ نعمتوں کا جہان ہوگا جس میں وہ ٹھہرے ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر خوشحالی کے جلوے ہوں گے۔ (المطففین: 24) یہ صفات جنتیوں کی ہیں اور عورت ومرد دونوں کو شامل ہیں لہذا اِن سے جنتی مردوں کی سیرت، صورت اور وجاہت کا اندازہ بھی بخوبی کیا جاسکتا ہے۔
تاہم اگر چاہا جائے کہ مردوں کے حسن وجمال کو بیان کرنے کے لیے بھی ویسی ہی رنگین تشبیہات ملیں جیسی جنتی حسیناؤں کے لیے وارد ہیں تو وہ شاید نہ مل سکیں کیونکہ رنگین اور مترنم تشبیہات عموما ہر زبان میں زنانہ حسن کے لیے ہوتی ہیں اور انہی سے کلام میں وہ ترنم پیدا ہوتا ہے جس میں مردوں وعورتوں دونوں کو دلچسپی ہوتی ہے۔ نیز جنتی حسیناؤں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ شاید اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مومن خواتین جنت کو صرف مردوں کی جگہ نہ سمجھیں اور نہ ہی مرد اپنے آپ کو وہاں تنہا سمجھیں۔
نیز یہ بات سچ ہے کہ قرآن وحدیث میں جنت کی بہت بلیغ تصویر کھینچی گئی ہے لیکن درحقیقت جنت سننے کی نہیں، دیکھنے کی چیز ہے اور دیکھنے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس کی لذتوں اور ذائقوں کے جتنے پہلو ہمارے سامنے بیان ہوئے ہیں، وہ سب کے سب در اصل اجمالی خاکہ ہیں اور جنت کا جہاں بس انہی پہلؤوں میں محصور نہیں۔ قرآن وحدیث ہی کی نصوص سے یہ بات پوری صراحت اور بداہت کے ساتھ ثابت ہے۔ارشادِ ربانی ہے کہ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمنا دل کرتے ہیں اور آنکھوں کی لذت کا سامان بھی مہیا ہوگا۔ (الزخرف: 71) ایک اور جگہ فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ جنتیوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان پردۂ غیب میں پڑا ہوا ہے۔ (السجدہ: 17) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گذرا۔“ (صحیح البخاری، رقم 3244)
مفسرین کے اختلافی اقوال کا جائزہ
اب تک کی گفتگو اس تناظر میں تھی کہ قرآن وحدیث میں مذکور جنتی حسیناؤں کے اوصاف وخصائل جنت ہی میں پہلا جنم لینے والی حسیناؤں سے مخصوص نہیں، بلکہ ان میں وہ جنتی خواتین بھی شامل ہیں جو دنیا کے امتحان میں مردوں کے ساتھ شریک رہی تھیں، لیکن ہم گذشتہ سطور میں عرض کر چکے ہیں کہ بعض کتبِ تفسیر میں تخصیص کے اقوال بھی موجود ہیں۔ درجِ ذیل سطور میں انہی اقوال کی تنقیح مقصود ہے، لیکن اِن اختلافی اقوال کو جاننے سے قبل ایک بار پھر یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ مومن عورتوں کے جنت میں داخلہ کا کوئی منکر نہیں، غلط فہمی صرف یہ سمجھنے میں واقع ہوئی ہے کہ قرآن وحدیث میں اکثر وبیشتر جن جنتی حسیناؤں کا تذکرہ آتا ہے تو ان سے مراد صرف کلمہء کن کے ساتھ پیدا کی جانے والی حسینائیں ہوتی ہیں۔
ہمارے مطالعہ کی رو سے امام سیوطی نے ”تفسیر الدر المنثور“ میں شعبی کے حوالہ سے صرف وہ قول نقل کرنے پر اکتفاء کیا ہے جس کی رو سے ”حور“ کا مصداق کوئی اور ہو نہ ہو، مومن خواتین تو ہیں ہی اور تخصیص کا کوئی قول سرے سے نقل ہی نہیں کیا (شعبی کی عبارت چند سطروں بعد آجائے گی)، جبکہ علامہ شمس الدین محمد بن احمد الشربینی نے اپنی تفسیر ”السراج المنیر“ کے اندر صریح لفظوں میں تخصیص کے قول پر نکتہء اعتراض اٹھاتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے، جس کی عبارت بھی آئندہ سطروں میں ہم نقل کریں گے۔ اسی طرح مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے ”تفسیرِ مظہری“ میں جو گفتگو کی ہے، اس سے بھی بظاہر یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تخصیص کا قول مرجوح ہے۔ علاوہ ازیں تفسیرِ طبری اور تفسیر ابنِ کثیر وغیرہ میں سرے سے یہ اختلافی بحث چھیڑی ہی نہیں گئی اور نہ ہی تخصیص وتعمیم کا کوئی پہلو کہیں زیرِ بحث آیا ہے، بس لفظِ ”حور“ کا لغوی مفہوم واضح کرنے پر اکتفاء کیا گیا ہے اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ لغوی اطلاق واضح کرنے پر اکتفاء کرنا بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ حضرات تعمیم کے قائل ہیں۔
پھر جن تفاسیر میں یہ قول مذکورہے کہ ”حور“ کے اطلاق میں مومن خواتین شامل نہیں تو ان میں بھی در اصل اس قول کو ایک اختلافی واحتمالی قول کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ واحد قطعی تفسیر کے طور پر۔ نیز جن جن تفاسیر میں یہ قول مذکور ہے، ان میں سے بھی تفسیرِ جلالین، تفسیرِ قرطبی، تفسیرِ بغوی، تفسیرِ ابن قیم، اللباب فی علوم الکتاب، تفسیرِ مظہری اور تفسیرِ خازن وغیرہ میں یہ اختلافی نکتہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56اور 74کے تحت اٹھایا گیا ہے جس میں حورانِ بہشتی کی ایک صفت بتلائی گئی ہے کہ ”ان حوروں کو کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔“ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جنتی حسیناؤں کا ذکر سورۃ الرحمن سے قبل بھی قرآن میں کئی جگہ ہوا ہے، بلکہ اگر صرف ”حور“ کے لفظ کو لے لیجئے تو یہ بھی سورۃ الرحمن سے قبل سورۃ الدخان کی آیت 54 میں اور سورۃ الطور کی آیت 20 میں ذکر ہوچکا ہے، لیکن مذکورہ کتبِ تفسیر میں سورۃ الرحمن کے اندر ہی تخصیص کے قول کا زیرِ بحث آنا اور اس سے قبل گذر جانے والے کسی متعلقہ مقام پر اس کا زیرِ بحث نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ مصنفین کے نزدیک اگر تخصیص کا قول قابلِ وقعت ہے بھی تو اسے صرف سورۃ الرحمن کے اندر مذکور حوروں کے تذکرہ سے متعلق ہونا چاہئے، نہ کہ قرآن وحدیث میں مذکور جنتی حسیناؤں کے تمام احوال سے، اگرچہ خود اہلِ تخصیص کے اعتراف کے مطابق علماء کی ایک جماعت اس قدر تخصیص کی بھی قائل نہیں۔
تاہم تفسیرِ رازی، ابو السعود، صنعانی، بیضاوی، روح المعانی اور روح البیان میں یہ اختلافی بحث سورۃ الدخان کی آیت 54 کے تحت چھیڑی گئی ہے اور یہ وہ سب سے پہلا مقام ہے جہاں قرآن میں ”حور“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ان چند مصنفین کے نزدیک تخصیص کے اختلاف کا تعلق ان تمام مقامات سے ہونا چاہئے جہاں ”حور“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ وہ تمام مقامات جہاں جنتی حسیناؤں کے احوال مذکور ہیں، خواہ وہاں ”حور“ کا لفظ ہو یا نہ ہو، وہ ان مصنفین کے نزدیک اس تخصیص کی لپیٹ میں ہونے چاہئیں، کسی طور درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ایسے کئی مقامات سور ۃ الدخان سے پہلے بھی قرآن میں موجود ہیں جن کی طرف اشارہ گذشتہ سطور میں کیا جاچکا ہے اور اس صورت میں تخصیص کی اختلافی بحث کو وہاں مذکور ہونا چاہئے تھا جہاں سب سے پہلے قرآن میں جنتی حسیناؤں کا ذکر آیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
تفاسیر کے اس تمہیدی جائزہ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ تخصیص کے اس دوسرے قول کی بنیاد کیا ہے؟
(1) ابنِ قیم اور قرطبی کے مطابق سورۃ الرحمن کی آیت میں حوروں کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اَن چھوئی ہوں گی، یہ صرف جنت ہی میں پہلا جنم لینے والی حسیناؤں میں پائی جاتی ہے کیونکہ مومن خواتین تو اس سے قبل دنیا میں چھوئی جاچکی ہیں۔ اس استدلال کے ضعف کو سمجھنے کے لیے صرف ایک نکتہ پہ غور کیجئے کہ سورۃ الواقعہ کی آیت35 میں جنتی حسیناؤں کو ”کنواری“ بھی فرمایا گیاہے اور گذشتہ سطور میں گذر چکا ہے کہ صحیح سند سے منقول ایک صریح حدیثِ نبوی کی رو سے وہ مومن خواتین بھی اس کے اطلاق میں شامل ہیں جو دنیا کے اندر بوڑھی ہو کر مری تھیں۔ اب اگر سن رسیدہ بوڑھیاں جنت میں جاکر کنواری ہوسکتی ہیں تو پھر ”اَن چھوئی“ کیوں نہیں؟ سورۃ الرحمن میں ذکر تو جنت والے جنم کا ہے اور اس جنم کی رو سے ظاہر ہے کہ مومن خواتین بھی جیساکہ کنواری ہوں گی، ویسا ہی اَن چھوئی بھی ہوں گی۔ جلیل القد تابعی امام شعبی نے ”الرحمن“ کی آیت کو صریحا ”الواقعہ“ کی آیت نمبر 35 پر قیاس کیا ہے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں:
”أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي في قولہ: لم يطمثهن إنس قبلھم ولا جان؛ قال: ھن من نساء أھل الدنيا خلقھن اللہ في الخلق الآخر كما قال: إنا أنشأناھن إنشاء فجعلناھن أبكارا؛ لم يطمثھن حين عدن في الخلق الآخر إنس قبلھم ولا جان!“ (الدر المنثور۔ الرحمن: 56)
”سعید بن منصور اور ابن المنذر نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الرحمن کی آیت میں حوروں کی جو صفت ”ان چھوئی“ بتلائی گئی ہے، وہ جنت میں جانے والی دنیا کی خواتین سے متعلق ہے کیونکہ انہیں وہاں ایک نیا جنم ملے گا، چنانچہ سورۃ الواقعہ میں انہیں کنواری بھی کہا گیا ہے، وجہ ظاہر کہ وہ اپنے نئے جنم میں ”ان چھوئی“ ہی ہوں گی۔“
اسی طرح تفسیر ”السراج المنیر“ میں قائلینِ تخصیص کے اس استدلال کو اسی بنیاد پر مسترد کیا گیا ہے:
”وقيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن ھن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين، يخلقن في الآخرۃ علی أحسن صورۃ، قالہ الحسن البصري، قال ابن عادل: والمشھور أن الحور العين لسن من نساء أھل الدنيا، إنما ھنّ مخلوقات في الجنۃ لأنّ اللہ تعالی قال:لم يطمثھن إنس قبلھم ولا جانّ؛ وأكثر نساء أھل الدنيا مطموثات. انتھی. لكن مرّ أنہ لم يطمثھن بعد إنشائھن خلقاً آخر وعلی ھذا لا دليل في ذلك“ (تفسیر السراج المنیر۔ الرحمن: 72)
یعنی ”ایک قول ہے کہ قرآن میں مذکور حورانِ بہشتی سے نبیوں اور مومنوں کی مومن بیویاں مراد ہیں، انہیں آخرت میں ایک حسین وجمیل سراپا عطا ہوگا، حسنِ بصری اسی کے قائل ہیں، جبکہ ابنِ عادل کہتے ہیں: مشہور بات یہ ہے کہ حورانِ بہشتی دنیا کی عورتوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ جنت ہی میں پہلا جنم لینے والی خواتین ہیں کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ”ان چھوئی“ ہیں اور دنیا کی اکثر عورتیں تو دنیا میں زیرِ استعمال رہی تھیں، لیکن پہلے بیان ہوچکا ہے کہ ان کا نیا جنم ”ان چھوا“ ہی ہوگا لہذا یہ کوئی وجہِ استدلال نہیں۔“
(2) روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی بھی تخصیص کے قائل ہیں، انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ روایات کی رو سے حورانِ بہشتی مٹی کی بجائے زعفران، مشک اور کافور سے یا پھر ملائکہ کی تسبیح سے تخلیق کی گئی ہیں، تاہم اول تو ان روایات کی استنادی حیثیت واضح نہیں، دوسرا اگر یہ سب صحیح بھی ہوں تو روایات میں جنت کے اندر حاصل ہونے والے وجود کی بات ہو رہی ہے اور جنت کے اندر دنیا کی مومن بیبیوں کو بھی ایک نیا وجود حاصل ہونا ہے، اس لیے اگر اُن کا وجود بھی جنت میں کافور وزعفران کے اسی خمیر سے اٹھایا جائے جس خمیر سے جنت میں پہلا جنم لینے والی حسیناؤں کا وجود تخلیق ہوگا اور روایات کے بیان میں دنیاکی مومن عورتیں بھی شامل ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟
(3) تفسیر رازی اور ابو السعود میں ابوہریرہؓ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ”لسن من نساء الدنيا“ یعنی ”حوریں دنیا کی عورتوں میں سے نہیں“، تاہم اول تو ابو ہریرہؓ کے اس قول کی بھی کوئی سند معلوم نہیں، جبکہ حسن بصری نے نو صحابہ کرام سے اس کے برعکس یہ نقل کیا ہے کہ حوروں سے مراد مومن عورتیں ہیں اور اس روایت کی سند بھی موجود ہے، نیز یہی قول شعبی اور کلبی کا بھی ہے اور اگر ابوہریرہؓ کا قول ثابت بھی ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ جنتی حسینائیں دنیا کی خواتین جیسی نہیں۔
(4) روح البیان کے مصنف نے لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک دنیا کی خواتین ”حور“ کے اطلاق میں شامل نہیں،تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آخر کس بنیاد پر جمہور کی طرف اس قول کی نسبت کر رہے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ متقدمین میں سے صرف ابو ہریرہؓ سے یہ قول منسوب ہے لیکن وہ بھی مدعا کے اثبات کے لیےکافی نہیں۔ ہماری نظر میں زیادہ سے زیادہ تخصیص کے قول کو ایک مشہور بات کہا جا سکتا ہے جیساکہ تفسیرِ قرطبی، اللباب فی علوم الکتاب، تفسیر السراج المنیر اور التفسیر المنیر(وہبۃ الزحیلی) میں کہا گیا ہے، جبکہ کسی بات کا محض ”مشہور“ ہونا اسے یہ سند فراہم نہیں کرتا کہ جمہور اہلِ علم کا علمی نکتہء نظر بھی یہی رہا ہو۔چنانچہ ہمارے نزدیک یہ بات غلط طور پر مشہور رہی ہے اور بعد کے مفسرین میں سے اگر کئی ایک نے تخصیص کوبظاہر ترجیح دیا ہے تو وہ بھی غالبا اسی مشہور غلط فہمی کے زیرِ اثر ہے، نیز شاید کوئی مضبوط بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے ہی خود ان کے ہاں بھی عموما تخصیص کے حق میں کوئی زیادہ شدت نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ”حور“ کے لغوی اطلاق کو بنا کسی دلیل کے ایک خاص جنس کی مخلوق سے مخصوص کر دینے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔
آخری بات
بعض لوگ حورانِ بہشتی کے تذکرہ کو دنیاوی تلذذ اور جگت بازی کا ذریعہ بناتے ہیں، حالانکہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی پوجا اختیار کرے، اپنے سجدوں کو طویل کردے، کم زوروں پر رحم کھائے، زندگی کی روش بدلے اور دنیاوی خواہشات کی بجائے اخروی مقاصد کا اسیر بنے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو معمور فرما دیں، اپنے لیے جینے مرنے کا سلیقہ سکھا دیں اور ایسا بنا دیں کہ جنت کو پانے کے ہم قابل ہوسکیں۔
گذشتہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ”حور“ کا لفظ قرآن وحدیث میں بالعموم تمام جنتی حسیناؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے (خواہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہونے والی ہوں یا دنیا کی مومن عورتیں) اور اس کا معنی ”جاذبِ نظر حسینائیں“ ہے۔ نیز قرآن وحدیث میں جہاں جنتی حسیناؤں کا تذکرہ آتا ہے تو اسے صرف کلمہء کن کے ساتھ پیدا ہونے والی حسیناؤں سے متعلق سمجھنا (یا مومن مردوں کو بھی ساتھ شامل کرد ینا) ایک تکلف ہے۔مزید یہ کہ ان تذکروں میں مومن خواتین کے لیے بھی رغبت کا پورا پورا سامان موجود ہوتا ہے اور اس پہلو کو اجاگر کرنا ہی قرآن کی صحیح ترجمانی کا ایک لازمی تقاضا ہے۔واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
فتوی و قضاء میں فرق اور مسئلہ طلاق میں بے احتیاطی
حضرات مفتیان کرام کی خدمت میں ایک گزارش
مفتی عبد اللہ ممتاز قاسمی سیتامڑھی
اللہ تعالی نے دین اسلام کو تاقیامت انسانوں کی رہنمائی کے لیے برپا کیا ہے، اس کے انفرادی، خاندانی، معاشرتی،ملکی اور سیاسی زندگی میں دائمی و آفاقی انتہائی منظم ومستحکم اصول موجود ہیں؛ لیکن بہت سی مرتبہ ہمارے ان اصولوں کے صحیح انطباق نہ کرسکنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی خرابیاں رونما ہوتی ہیں؛ خصوصا رہنمایان دین وشریعت کی ذرا سی چوک امت میں سخت تباہی وبربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔
دنیا کے اندر صدیوں تک اسلامی حکومت برپا رہی ہے اور مسلم حکام اپنی کوتاہیوں کے باوجود اپنے عدالتی نظام کو اسلامی آئین وضوابط کے تحت چلاتے رہے ہیں، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ وفاطمیہ ہر دور میں دارالقضاءکا مضبوط سسٹم رہا ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ خلافت عثمانیہ کے سنہرے دور کے بعد ختم ہوگیا۔ جب خلافت ختم ہوئی تو دارالقضاءکا اسلامی نظام بھی جاتا رہا؛ چناں چہ حضرات مفتیان کرام نے قاضیوں کی ذمے داریاں بھی سنبھالنی شروع کردیں جس کی وجہ سے ”فتوی و قضاءکا فرق“ جاتا رہا اور فقہی کتابوں میں جو مسائل قضاءکے لیے لکھے گئے تھے، حضرات مفتیان کرام نے ان کے مطابق فتوی دینا شروع کردیا۔حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
والمُفتُونَ الیوم غافلون عنہ، فان اکثرہم یفتونَ باحکامِ القضاء. ووجہ الابتلاءفیہ: ان المذکور فی کتب الفقہ عامۃ ہو مسائل القضاء، وقَلَّما تُذکرُ فیہا مسائلُ الدِّیانۃ. نعم، تذکر تلک فی المبسوطات، ولا تُنَال الا بعد تدرُّبٍ تامٍ، ولعل وجہتہ ان القاضی فی السلطنۃ العثمانیۃ لم یکن ینصبُ الا حنفیًا، بخلاف المفتیین فانہم کانوا من المذاہب الاربعۃ، وکان القاضی الحنفی یُنَفِّذُ ما افتُوا بہ، فشرع المُفتُونَ تحریر حکم القضاء لینفِّذ القاضی، فاشتہرت مسائل القضاءفی الکتب، وخملت مسائل الدیانۃ، ثم لا یجبُ ان تتفقَ الدیانۃ والقضاء فی الحکم بل قد یختلفان۔ (فیض الباری علی صحیح الباری:1/ 272)
’’آج کے مفتی حضرات اس (فتوی و قضاءکے فرق)سے غافل ہیں؛ چناں چہ اکثر مفتیان احکام قضاءکے مطابق فتوی دے رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ متوسط فقہی کتابوں میں عام طور سے قضائی احکام لکھے ہوے ہیں اور بہت کم دیانت (فتوی) کے مسائل کا ذکر ہے؛ ہاں مبسوطات میں دیانت کے مسائل کا ذکر ہے؛ لیکن ان (کتابوں کے مسائل دیانت) کو مکمل مشق وتمرین سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (قضاءکے مطابق فتوی کے چلن کے عام ہوجانے کی) وجہ شاید یہ ہے کہ عثمانی سلطنت میں قاضی کے عہدے پر صرف حنفی مامور ہوا کرتے تھے، جب کہ مفتیان مذاہب اربعہ کے تھے، اس لیے حنفی قضاۃ ان مفتیوں کے فتوے کے مطابق فیصلہ کردیا کرتے تھے؛ چناں چہ مفتیوں نے قضاءکے احکام لکھنا شروع کردیا تاکہ قاضی اس حکم قضائی کو نافذ کریں۔ اس طرح کتابوں میں قضاءکے مسائل عام ہوتے چلے گئے اور دیانت (فتوی) کے مسائل ختم ہوتے چلے گئے۔جب کہ ہمیشہ قضاءاور دیانت کا حکم شرعی یکساں نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ دونوں کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔“
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ متاخرین کے دور میں قاضیوں کا علمی معیار گرگیا تھا، قضاۃ کی تقرریاں علمی بنیاد پر کم اور قرابت داری کی بنیاد پر زیادہ ہونے لگی تھی اس لیے متاخرین نے قاضی کے فیصلے کو فتوی کے تابع کردیا تاکہ قاضی اپنی کم علمی کی وجہ سے کچھ غلط فیصلہ نہ کردے ۔ شامی نے لکھا ہے : ”القضاء تابع للفتوی فی زماننا لجہل القضاۃ“ کہ قاضیوں کی جہالت کی وجہ سے اس زمانے میں قضاءفتوی کے تابع ہے یعنی مفتی قضائی حکم لکھ دیتا تھا اور قاضی اس حکم کی تنفیذکرتا تھا ۔ یہ چلن اتنا عام ہوگیا تھااور دھڑلے سے مفتیان قضائی حکم فتوی میں لکھنے لگے تھے کہ شامی کو فتاوی شامی میں کئی بار توجہ دلانی پڑی کہ عام لوگ جب مسئلہ دریافت کرنے آ ئے تو مفتی کے لیے ضروی ہے کہ دیانت کے مطابق فتوی دے ؛ البتہ اس فتوی میں”لا یصدق قضاءا“ کی صراحت کردے کہ دارالقضاءمیں اس فتوے کا اعتبار نہ کیا جائے تاکہ قاضی اس فتوی کی روشنی میں غلط فیصلہ نہ کردے۔ (و اذا کتب المفتی یدین) ای کتب ہذا اللفظ بان سئل مثلا عمن حلف واستثنی ولم یسمع احدا یجیب ای لا یحنث فیما بینہ وبین ربہ ولکن یکتبہ بعدہ ”ولا یصدق قضاءا“ لان القضاءتابع للفتوی فی زماننا لجہل القضاۃ فربما ظن القاضی انہ یصدق قضاءا ایضا۔ (شامی: ۶۱۲۴)
تتبع وتلاش سے ایسے ڈھیر سارے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے؛ جن میں قضاءودیانت کا فرق نہیں کیا جا رہا ہے اور اس بات کے قائل علامہ کشمیریؒ جیسی شخصیت ہیں؛ لیکن آج ہم معاشرہ کی بیخ کنی کرتے انتہانی سنگین وحساس مسئلہ یعنی طلاق کے حوالے سے قضاء ودیانت کا فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی بے احتیاطیوں پر گفتگو کریں گے۔
آئیے سب سے پہلے ہم دیانت وقضاءمیں فرق سمجھتے ہیں!
فتوی احکام شرعیہ کے متعلق اِخبار محض کا نام ہے۔ علامہ قرافیؒ لکھتے ہیں: الفتوی محض اخبار عن اللہ تعالی فی الزام او اباحۃ۔ (انوار البروق فی انواءالفروق:4/89) لہذا مفتی کی ذمے داری بس''صورت مسئولہ کے مطابق حکم شرعی بتادینا ہے ، قطع نظر اس کے کہ صورت مسئولہ نفس الامر کے مطابق ہے یا خلاف۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں: یقول المفتی ''الحکم فی الصورۃ المسئول عنہا کذا'' ولا یلزم منہ ان تکون الصورۃ المسئول عنھا موافقۃ للواقع فی نفس الامر۔ (اصول الافتاءوآدابہ:12) قاضی نفس الامر اور وجود خارجی کو جاننے کا مکلف ہے جب کہ مفتی کا یہ کام قطعی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: القاضی الحاکم یحتاج الی معرفۃ المسائل والوقائع ایضا بخلاف المفتی۔ (العرف الشذی شرح سنن الترمذی:3/ 69)
اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ قضاءکا اپنا میدان ہے اور دیانت یعنی فتوی کا اپنا میدان ہے، دونوں کو اپنے حدود میں رہنا اور ان کی پاسداری کرنا چاہیے۔ متعدد فقہاءنے لکھا ہے کہ قاضی کے لیے فتوی دینا جائز نہیں ہے اور اس پر تقریبا تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو معاملہ قاضی کے زیر سماعت ہو اس مسئلہ میں قاضی کے لیے فتوی دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی مفتی حضرات کے لیے قضاءکے میدان میں جانا اور دیانت سے بڑھ کر قضائی احکامات کے مطابق فتوی دینا درست نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پر جانے سے پہلے بطور تمہیدچند باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے۔
ایک مجلس میں ایک سے زائد طلاق کی دو شکلیں ہیں۔
اول: کوئی یوں کہے ”میں نے تم کو تین طلاق دی“ یا ”ایک طلا ق دو طلا ق تین طلاق“
دوم: تین مرتبہ”طلاق طلاق طلاق“ کہہ دے۔
اول الذکر سے تین طلاق واقع ہوجائے گی، اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ثانی الذکر کی تین شکلیں ہیں۔
اول: ”طلاق طلاق طلاق“ کہے اور تاسیس/استیناف کی نیت کرے یعنی ہر مرتبہ طلاق میں نئی طلاق کی نیت کرے۔
ثانی: ”طلاق طلاق طلاق“ کہے اور تاکید کی نیت کرے، یعنی اس کی نیت تو ایک ہی طلاق کی ہے؛ البتہ دوسری اور تیسری طلاق کے تکرار سے طلاق کو موکد کرنا مقصد ہے۔
ثالث: ” طلاق طلاق طلاق“ کہے اور اس کی نیت تاسیس یا تاکید میں سے کچھ بھی نہ تھی۔
اس میں بھی شکل اول میں تین طلاق واقع ہوجائے گی، ہماری گفتگو آخری شکل میں مذکوردوسری اور تیسری شکل پر ہوگی۔یعنی تین مرتبہ ''طلاق طلاق طلاق '' کہے اور نیت ایک طلاق کی تھی یا نیت کچھ بھی نہ تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دو سالوں تک ایسی طلاق جو تین مرتبہ ”طلاق طلاق طلاق“ کہہ دی جاتی تھی ایک طلاق سمجھی جاتی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلن بدل جانے اور دیانت کے کم ہوجانے کی وجہ سے اس پر بندش لگادی اور فرمایا کہ تین مرتبہ کہی ہوئی طلاق تین طلاق شمار ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے:
کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافۃ عمر طلاق الثلاث واحدۃ، فقال عمر بن الخطاب: ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ اناۃ، فلو امضیناہ علیہم، فامضاہ علیہم ۔ (صحیح مسلم:2/1099)
معروف شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:
فالاصح ان معناہ انہ کان فی اول الامر اذا قال لہا انت طالق انت طالق انت طالق ولم ینو تاکیدا ولا استئنافا یحکم بوقوع طلقۃ لقلۃ ارادتہم الاستئناف بذلک فحمل علی الغالب الذی ہو ارادۃ التاکید فلما کان فی زمن عمر رضی اللہ عنہ وکثر استعمال الناس بہذہ الصیغۃ وغلب منہم ارادۃ الاستئناف بہا حملت عند الطلاق علی الثلاث عملا بالغالب السابق الی الفہم منہا فی ذلک العصر وقیل المراد ان المعتاد فی الزمن الاول کان طلقۃ واحدۃ وصار الناس فی زمن عمر یوقعون الثلاث دفعۃ فنفذہ عمر۔ (شرح النووی علی مسلم: 10/72)
’’اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ شروع زمانے میں جب کوئی ”انت طالق، انت طالق، انت طالق“ (تمھیں طلاق ہے، تمھیں طلاق ہے، تمھیں طلاق ہے) کہہ کر طلاق دیتا اور تاکید واستیناف (نئی طلاق کے وقوع) کسی بھی چیز کی نیت نہ کرتا تو ایک طلاق کے وقوع کا حکم لگتا تھا؛ کیوں کہ لوگ ان الفاظ سے بہت کم استیناف (نئی طلاق کے ایقاع) کا ارادہ کرتے تھے، لہذا ان الفاظ کو ان عام معمول پر محمول کیا جاتا جسے تاکید کہا جاتا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور طلاق کے لیے ان الفاظ کا استعمال بکثرت ہونے لگا اور عام طور سے ان کی نیت استیناف کی ہوتی تھی؛ چناں چہ مطلق تین مرتبہ (طلاق طلاق طلاق کہنے) کو تین طلاق پر محمول کیا گیا اسی سابقہ غالب معمول پر عمل کرتے ہوئے۔“
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ قضائی معاملہ کے لیے تھا، دیانت کے لیے قطعا نہیں تھا؛ چوں کہ قاضی کا کام ظاہر کے مطابق حکم شرعی لگانا ہے، اور اس نے تین مرتبہ ''طلاق طلاق طلاق''کہہ دی ہے تو ظاہر یہی ہے کہ اس نے تین طلاق دی ہوگی؛ لیکن مفتی کاکام دیانت کے مطابق فتوی دینا ہے، وہ قضائی حکم کے مطابق فتوی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر کسی نے تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہہ دی تو مفتی کے لیے مطلق تین طلاق کا فتوی لکھ دینا درست نہیں ہے۔
اب آئیے ہم ہندوستانی وپاکستانی معاشرہ کی صورت حال اور چلن کو دیکھتے ہیں!
یہاں عام چلن ہے کہ نکاح کے وقت نکاح خواں تین مرتبہ قبول کراتا ہے ”قبول ہے قبول ہے قبول ہے“ کے الفاظ سے ، اس لیے کم پڑھے اوراَن پڑھ لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ جب تک تین مرتبہ طلاق طلاق طلا ق نہیں کہیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی؛ چوں کہ تین مرتبہ قبول کیا تھا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ فلمی کہانیاں اور ڈرامے معاشرے کو دیکھ کر بنتی ہیں یا فلموں سے متاثر ہوکر معاشرہ بنتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ فلموں اور سیریلوں کا معاشرہ سے ڈائریکٹ کنکشن (رابطہ)ہے، گوکہ فلم بینی حرام ہے؛ لیکن اس نے ہمارے معاشرے کو بھی متاثر کیا ہے، فلموں اور سیریلوں میں طلاق کا تصور یہی دیا اور سمجھایا گیا ہے کہ جب تک تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق نہ کہی جائے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ شاید ہی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نارمل حالت میں طلاق دی گئی ہو ورنہ عام طور سے غصہ کے عالم میں ہی طلاق کی نوبت آتی ہے، ایسے میں انسان بس ''طلاق طلاق طلاق'' کہہ دیتا ہے، اس کی نیت استیناف یا تاکید کی نیت نہیں ہوتی ہے۔
اس صورت حال کو جاننے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں۔
1۔ اگر کوئی تین مرتبہ ''طلاق طلاق طلاق'' کہہ دے اور معاملہ دارالقضاءآئے تو قاضی ثبوت وشواہد کی روشنی میں صورت حال کا جائزہ لے کر اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کریں ۔اگر فیصلہ میں خطا ہوبھی گیا تو وہ ایک اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔
2۔ اگر معاملہ دارالافتاءآئے اور وہ بصراحت کہے کہ میری نیت ایک کی تھی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔
3۔ اگر معاملہ دارالافتاءآئے اور استفتاءمیں اپنی نیت استیناف/تاکید کی صراحت نہ ہو تومفتی اس نیت کی وضاحت طلب کرے اور مستفتی کی وضاحت کے مطابق فتوی دے یعنی اگر وہ تاکید کی نیت بتائے تو تاکید اور استیناف کی نیت بتائے تو استیناف۔
4۔ اگر معاملہ دارالافتاءآئے اور وضاحت طلب کرنے پر جواب آئے کہ ''میری کوئی نیت نہ تھی، بس تین بار طلاق طلاق طلاق کہہ دی'' تو اسے معاشرہ کی صورت حال کی وجہ سے ایک طلاق سمجھی جائے اور ایک طلاق کا فتوی دیا جائے۔جیسا زمانہ نبوی، خلافت صدیقی اورخلافتِ فاروقی کے ابتدائی دو سالوں میں ہوتا رہا ہے۔
پیدا ہونے والے اشکالات کے جوابات:
نمبر پر ایک پر یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اگر قضائی تھا تو پھر موجودہ وقت کے قضاۃ حضرات کو اپنی صوابدید کے مطابق وقوع اور عدم وقوع طلاق کے فیصلہ کا اختیار کیسے دیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو وقوع طلاق کا فیصلہ کیا تھا اس کی دو وجہ تھی ۔
۱۔ چلن کا بدل جانا
۲۔ دیانت کا کم ہوجانا
موجودہ حالات میں دیانت کی کمی تو دور عمری سے ہزار گنا زائد ہے؛ لیکن ہمارے یہاں دینی شعور کی کمی اور جہالت کی وجہ سے چلن پھر سے بدل چکا ہے اور چلن بدل جانے کی وجہ سے قاضی رواج کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے۔ مجموعہ قوانین اسلامی میں ہے:
”اور اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی اور ا س نے محض زور پیدا کرنے کے لیے الفاظ طلاق دہرائے ہیں، اس کا مقصد ایک سے زائد طلاق دینا نہیں تھا تو اس کا یہ بیان حلف کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی کچھ بھی نیت نہیں تھی، نہ ایک کی اور دو یا تین کی، دیکھا جائے گاکہ عرف میں ایسے مواقع پر تاکیدا الفاظ دہرانے کا رواج ہے یا نہیں ، اگر عرف غالب یہ ہوکہ ایسے مواقع پر لوگ محض کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بار بار اسی لفظ کو دہراتے ہیں تو عرف کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوے الفاظ کی تکرار کو تاکید پر محمول کرکے ایک ہی طلاق واقع کی جائے گی۔ (مجموعہ قوانین اسلامی: ۴۹۱)
چنانچہ بینہ وثبوت اور عرف کو ملحوظ رکھ کر قاضی ایک یا تین کا فیصلہ کرسکتے ہیں ، اگر وہ مصیب ہوے تو دو اجر کے مستحق ہوں گے اور اگر مخطی ہوے تو ایک اجر کے ۔ ارشاد نبوی ہے : اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب، فلہ اجران، واذا حکم فاخطا فلہ اجر واحد (ترمذی: 1326)
نمبر دو اور تین پر حضرات مفتیان کرام کی طرف سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس طرح لوگ تین کی نیت سے طلاق دیں گے اور ایک کا فتوی حاصل کرلیں گے۔ جواب بڑا سادہ اور سیدھا ہے کہ ہمارا تو کام ہی”اِخبار محض“ ہے، اس نے زبان یا تحریر سے جیسا بتایا ہمارا کام اس کے مطابق فتوی دے دینا ہے، اب معاملہ فیما بینہ وبین اللہ ہے۔اگر اس نے جھوٹ بول کر آپ سے فتوی حاصل کیا ہے یعنی اس کی نیت استیناف کی تھی اور ”تاکید کی نیت یا بلا نیت“ کہہ کر ایک طلاق کا فتوی حاصل کر لیا تو یقینا اس کا مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا، عنداللہ اس کا جوابدہ وہ خود ہوگا؛ لیکن اگر اس کی نیت وہی تھی جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے یعنی تاکید کی تھی یا بلا نیت تھی اور آپ نے تین طلاق کا فتوی لکھ کر اس کے گھر کو توڑ دیا، ان کے بچوں کو بکھیردیا اور طلاق کی وجہ سے جو انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی پر ہوے تو یقینا کہیں نہ کہیں اس جرم میں آپ کا شمار ہوگا اور اس طلاق کی وجہ سے ہونے والے تمام تر برے اثرات کے آپ ذمہ دار ہوں گے اوراس کے لیے عنداللہ جوابدہ ہونا پڑے گا۔ جان لیجیے! اسے ”اجتہادی خطا“ کہہ کر بھی نہیں ٹالا جاسکے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے حدیث : اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب، فلہ اجران، واذا حکم فاخطا فلہ اجر واحد. (ترمذی: 1326) کے متعلق عقد الجید شاہ ولی اللہ محدث ہلویؒ کے حوالے سے حاشیہ لکھا ہے:
ان حدیث الباب فی حق القاضی لا فی حق المفتی او المجتہد والقاضی الحاکم یحتاج الی معرفۃ المسائل والوقائع ایضا بخلاف المفتی (العرف الشذی شرح سنن الترمذی:3/69)
’’ حدیث مذکور قاضی کے حق میں ہے نہ کہ مفتی یا مجتہدکے حق میں (کہ اگر وہ مصیب رہا تو دو گونا اجر اور اگر مخطی رہا تو ایک گونا اجر) چوں کہ قاضی مسائل جاننے کے ساتھ تحقیق واقعہ کا بھی مکلف ہے، برخلاف مفتی کے (کہ انھیں تحقیقی واقعہ کی ضرورت نہیں۔ان کے لیے مسائل کا علم کافی ہے) “
نمبر دو والی شکل کو اگر آپ بغور دیکھیے تواس مسئلہ کو لے کر دارالافتاءآنے والے ہر شخص کو آپ جھوٹا اور فریبی فرض کرکے فتوی لکھتے ہیں، یعنی جتنے بھی آدمی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے اور وہ آپ سے فتوی طلب کرے گوکہ وہ سچااور دین دارآدمی ہے ، خوف خدا کی وجہ سے دارالافتاءآیا ہے؛ لیکن آپ بلا کسی دلیل کے اسے جھوٹا مان لیتے ہیں کہ یقینا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر قضاءکے مطابق تین طلاق کا فتوی لکھ دیتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ اصول فتوی اور اصول شریعت دونوں کے خلاف ہے ۔
نمبر دو پر ہونے والے اعتراض کا واضح جواب یہ بھی ہے کہ اس اندیشہ کو تمام اہل مراجع نے محسوس نہیں کیا؛ بلکہ انھوں نے بصراحت لکھا کہ اگرمستفتی اقرار کرتا ہے کہ اس نے تین مرتبہ طلاق طلاق طلا ق کہی ہے؛ لیکن نیت ایک کی تھی تو مفتی ایک طلاق کے وقوع کا ہی فتوی دے گا۔
نمبر چار پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ زمانہ نبوی اور خلافت صدیقی میں چوں کہ تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہنے کے باوجود ایک کی نیت کا ہی چلن تھا جیسا کہ امام نوویؒ کی عبارت سے واضح ہے؛ لیکن اب ایسی صورت حال نہیں ہے۔ اس کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے کہ زمانہ اب بھی وہی ہے، اب بھی لوگ تین مرتبہ طلا ق طلاق طلاق کہہ کرایک طلاق واقع ہونا ہی سمجھتے ہیں، بس ایسا سمجھنے کی وجہ میں فرق ہے، قرن اول میں ایمان کی پختگی، شرعی علوم سے گہری واقفیت اور عنداللہ جوابدہی کے خوف سے ایسا چلن تھا، اب جہالت، شرعی علوم سے ناواقفیت اور فلم وسیریل بینی کے اثر سے ایسا چلن ہے۔ بہرحال نتیجہ کے اعتبار سے دونوں کی صورت حال برابر ہے اس لیے حکم شرعی بھی برابر لگنی چاہیے، یعنی جو حکم پہلے لگتا تھا وہی حکم اب بھی لگنا چاہیے۔مجموعہ قوانین اسلامی کا حوالہ گزر چکا ہے۔
اسی قبیل سے جھوٹی طلاق کے اقرار کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہہ دے کہ ''میں تمھیں طلاق دے چکا ہوں'' یا کسی نے اس کی بیوی کو زبردستی طلاق دلانے یا طلاق نامہ پر دستخط کرانے کی کوشش کی اور اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکا ہے تو دیانۃ اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، یعنی مفتی حضرات وقوع طلاق کا فتوی نہیں دے سکتے؛ البتہ اگر معاملہ دارالقضاءجاتا ہے تو ثبوت وشواہد کی روشنی میں قاضی طلاق واقع کردے گا۔ فتاویٰ شامی میں ہے: المفتی یفتی بالدیانۃ) مثلا اذا قال رجل: قلت لزوجتی انت طالق قاصدا بذلک الاخبارکاذبا فان المفتی یفتیہ بعدم الوقوع والقاضی یحکم علیہ بالوقوع۔ (رد المحتار: 5/365)
مفتی کا کام دیانت کے مطابق فتوی دینا ہے؛ چناں چہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا ''انت طالق'' (تم مطلقہ ہو/تم کو طلاق دے چکا ہوں) اس ارادے کے ساتھ کہ وہ جھوٹی خبر دے رہا ہے تو مفتی عدم وقوع طلاق کا فتوی دے گا اور (اگر معاملہ دارالقضاءجاتا ہے تب) قاضی وقوع طلاق کا فیصلہ کرے گا۔
کسی نے اپنی بیوی کو ہنسی مذاق میں کہہ دیا کہ ''میں تمھیں طلاق دے چکا ہوں '' یا اپنے دوستوں کی مجلس میں تفریحا اقرار کیا کہ میں تو بیوی کو طلاق دے چکا ہوں تب بھی اس پر دیانۃ (فتوی کی رو سے) طلاق واقع نہ ہوگی۔ ولو اقر بالطلاق کاذبا او ھازلا وقع قضاءلا دیانۃ (رد المحتار:3/236)
مذکورہ بالا دونوں مسائل میں بھی دارالافتاءسے وقوع طلاق کے فتاوے صادر ہوتے ہیں اور ان کی مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النکاح، والطلاق، والرجعۃ۔ (ابوداود:2194) ہوتی ہے، جب کہ اس روایت کے حوالے سے” انشاءطلاق اور اخبار طلاق میں فرق“ اور اس کی وجہ سے قضاءودیانت کا فرق کرنا بھول جاتے ہیں ۔ یعنی اگر ان شاءطلاق ہنسی مذاق میں بھی واقع ہوجاتی ہے مثلاہنسی مذاق میں یوں کہہ دے کہ ”میں تمھیں طلاق دیتا ہوں“ تو طلاق واقع ہوجائے گی؛ لیکن اگر ہنسی مذاق میں اقرار طلاق کرلے کہ میں تمھیں طلاق دے چکا ہوں تو فتوی کی رو سے طلاق واقع نہ ہوگی؛البتہ قضاءکی رو سے طلاق واقع ہو جائے گی۔(حوالہ سابق دیکھیں) چوں کہ اگر ہنسی مذاق میں بھی کیے گئے اقرار کی بناءپر نکاح، طلاق اور رجعت کے احکام قضاکے اعتبار سے نافذ نہ کیے گئے تو معاملات خراب ہوجائیں گے اور قاضی کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہوجائے گا؛ کیوں کہ وہ ظاہر کے مطابق حکم لگانے کا مکلف ہے۔ اس کا مقصد ہزل تھا یا جد، اپنے قول میں وہ سچا تھا یا جھوٹاا س سے قاضی کو کوئی مطلب نہیں؛ چنانچہ اگر کسی شخص نے دو آدمی کو پہلے سے گواہ بنا دیا کہ میں اپنی بیوی کو جھوٹی طلاق کی خبر دوں گا، تم گواہ رہو اور بیوی کو جھوٹی طلاق کی خبر دے دی کہ ”میں تمھیں طلاق دے چکا ہوں /تم مطلقہ ہو“، اب اگر یہ معاملہ دارالقضاءجاتا ہے تب بھی قاضی وقوع طلاق کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ در مختار میں ہے: قال: انت طالق او انت حر وعنی الاخبار کذبا وقع قضاء، الا اذا اشہد علی ذلک۔ (الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین:3/293)
اس سے صاف واضح ہے کہ حدیث مذکور کا اطلاق عمومی نہیں ہے، بلکہ یہ امور قضا کے ساتھ مخصوص ہے، اگر حکم عمومی ہوتا جھوٹی تو طلاق سے پہلے گواہ بنانے یا نہ بنانے سے کچھ فرق نہ پڑتا اور بتقاضائے عموم بہرحال اس پر طلاق واقع ہوجاتی۔
بہرحال؛ ان سب کے باوجود دارالافتاوں کا چلن یہی ہے کہ ان سب مسائل میں وہ حکم قضاءکے مطابق فتوی لکھتے ہیں اور ان مقامات میں جہاں طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، وہاں بھی بے پروا ہوکر طلاق واقع کردیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ علامہ کشمیریؒ کے بقول دیانت وقضاءمیں فرق سے غفلت ہے اور متداول کتب فقہ میں جہاں بیشتر مسئلے قضاءکے لکھے ہوئے ہیں، ان کے مطابق فتوے لکھنا ہے۔ میرے تخمینہ کے مطابق دارالافتاوں میں ستر اسی فیصد سوالات طلاق یا میراث کے آتے ہیں جن میں چالیس سے پچاس فیصد سوالات طلاق کے ہوتے ہیں، یعنی معاشرہ طلاق کی آگ میں بری طرح جھلس رہا ہے۔ طلاق کی وجہ سے صرف میاں بیوی جدا نہیں ہوتے، بلکہ دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں پر جو سنگین اثرات پڑتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ انھیں بیان کرنے کے لیے مستقل ایک مقالہ چاہیے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ان مسائل پر توجہ دی گئی تو یقینا طلاق کی شرح معاشرہ سے کم ہوجائے گی اور اس لعنت کی وجہ سے برپا ہونے والے فساد جس سے قوم تباہ ہورہی ہے اور ان کا مستقبل خاکستر ہو رہا ہے، ان سے کسی حد تک بچ پانا ممکن ہوگا۔ اللہ کرے کہ ارباب فتاوی ،سنجیدہ علمی شخصیات اور درد مند اہل علم اس سنگین مسئلہ میں غور کریں اور امت جس مسئلہ سے بری طرح جھوجھ رہی ہے، اس سے انھیں نجات دلانے میں مدد کریں ۔اگر ضرورت پڑنے پر حضرت تھانوی ؒ دوسرے فقہ سے رجوع کرسکتے ہیں تو یقینا آپ اپنی ہی فقہی کتابوں میں موجود مسئلہ میںمحض دیانت وقضاءمیں فرق کرکے اور اپنا دائرہ کار متعین کرکے امت کے ایک بڑے طبقہ کو (جو پہلے سے ہی غریب ، مفلوک الحال اور ان پڑھ ہوتے ہیں )کا گھر ٹوٹنے اور مزید شکستہ حال ہونے سے بچا سکتے ہیں ۔اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وہو المصیب
ایک درخواست: یہ میرے ناقص فکر ومطالعہ اور علمی وعوامی تجربہ کا حاصل ہے، کوئی انسان لغزش وخطا سے خالی نہیں، اس لیے اگر اہل علم ونظر قارئین کو اس تحریر میں کوئی قابل اشکال پہلو یا لائق اصلاح بات نظر آئے تو نشان دہی فرمادیں ساتھ ہی اگر اس موضوع یا اس کے ذیلی ابحاث سے متعلق اضافی مواد آپ کے مطالعہ میں ہو تو آگاہ فرمائیں۔ بے حد شکر گزار ہوں گا۔
مدرسہ طیبہ میں سالانہ نقشبندی اجتماع
مولانا محمد اسامہ قاسم
الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام سالانہ نقشبندی اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کے مہمان خصوصی حضرت خواجہ خلیل احمد ہوتے ہیں۔ اس سال یہ دینی فکری اصلاحی نقشبندی اجتماع 21 دسمبر بروز سوموار مدرسہ طیبہ گوجرانوالہ میں منعقد ہوا۔ اس مبارک روحانی اجتماع میں حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب ،حضرت مولانا اشرف علی، مولانا شاہ نواز فاروقی، مولانا جمیل الرحمٰن اختر، مولانا فضل ہادی ، سید سلمان گیلانی، حافظ فیصل بلال حسان ، مفتی عبید الرحمن، مولانا عثمان رمضان، صاحبزادہ نصرالدین خان عمر اور مولانا امجد محمود معاویہ نے شرکت کی۔
قاری محمد عمر فاروق کی پرسوز تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ حافظ یحیی بن زکریا، حافظ عادل حسین اور حافظ فیصل بلال حسان نے نعتیہ کلام پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ نعتیہ کلام کے بعد صاحبزادہ حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے۔ علامہ زاہد الراشدی صاحب نے خواجہ صاحب کو اجتماع میں خوش آمدید کہا۔ خواجہ صاحب نے ختم خواجگان نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کے مطابق مجلس ذکر کرائی۔ پھر ایک عزیز کے انتقال کی اطلاع ملنے پر جنازے میں شرکت کے لیے جلد واپس تشریف لے گئے۔
نقشبندی محفل ذکر کے بعد جامعہ محمودیہ سرگودھا کے مہتمم حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اصلاح قلب، دینی مدارس اور خانقاہوں کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ۔ فرمایا کہ ہمارے پاس مسجد اور مدرسے کی نسبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ، ہم خوش نصیب ہیں کہ دین سیکھنے اور سکھانے والوں میں شمار ہوتے ہیں ۔ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے رنگ فروش اور ایک ہوتا ہے رنگ ساز۔ رنگ فروش رنگ بیچتا ہے لیکن رنگ ساز رنگ چڑھاتا ہے۔ مدارس اور خانقاہوں میں ادب اخلاق کا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ اہل دل علماء کی صحبت سے دل روشن اور منور ہوتا ہے۔ اکابرین کی صحبت اور معیت غنیمت ہے۔
پاکستان شریعت کونسل کے صوبائی امیر مولانا قاری جمیل الرحمن اختر صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جہاں بزرگ اکابرین موجود ہوں، وہاں اللہ ربّ العزت کی طرف سے انتہائی سکون اور راحت کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے رشتے ناطے توڑکر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے بغیرکہیں کامیابی،کامرانی اورخوشحالی کے منازل آسانی کے ساتھ طے کرلیں گے مگرحالات اورواقعات نے یہ ثابت کردیاہے کہ یہ سراسر بھول،نادانی اورخام خیالی کے سواکچھ نہیں۔ہمارے پاس آج دنیاکی ہرنعمت اورسہولت موجودہے لیکن اس کے باوجودہماری زندگیوں میں چین ہے اورنہ سکون۔سب کچھ پاس ہونے کے باوجودبے چینی اوربے سکونی سے ایسالگ رہاہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔اس کے مقابلے میں اگر اللہ کے دوستوں کی چندسیکنڈز کی قربت اورصحبت بھی اختیارکرلی جائے توپھر ہمارے جیسے گنہگاربھی لمحوں میں خالی ہاتھ دنیاجہان کے سارے غم بھول جاتے ہیں۔
شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی نے بھرپور انداز میں خوبصورت نئے کلام پڑھ کر محفل کو مزید بارونق بنا دیا گیلانی صاحب کے اس مشک بار کلام پہ خوب داد دی گئی۔
درودِ پاک میں تسکین ہے دلوں کے لیے
درودِ پاک اجالا ہے ظلمتوں کے لیے
درود پاک میں برکت خدا نے رکھی ہے
درود پاک میں پڑھتا ہوں برکتوں کے لیے
عصر کی نماز کے بعد اجتماع کی آخری نشست سے خطاب کرتے ہوئے خطیب اسلام مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب اپنی گفتگو میں کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جسم کالوتھڑا یہ دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک اور اگر یہ دل خراب تو سارا جسم خراب ، انہوں کہا کہ جسم بمنزلہ محکوم اور رعایا کے ہے جبکہ یہ دل بمنزلہ حاکم کے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اپنے حاکم اور بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں اسی طرح سارا جسم بھی دل کی مان کر چلتا ہے۔ جو دل نے کہنا ہے جسم نے وہی کرنا ہے، دلوں کی صفائی اور تزکیہ نفس کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے ۔ یہ دل دو طرح سے صاف ہو سکتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت و معیت سے دلی کیفیات میں نکھار اور ایمانی جذبات میں قوت آتی ہے۔
الشریعہ اکادمی کے ڈائریکٹر علامہ زاہد الراشدی صاحب نے روحانی نقشبندی اجتماع سے آخری خطاب کرتے ہوئے خواجہ خلیل احمد صاحب کی تشریف آوری اور تمام شرکاء کی اجتماع میں شرکت پر سب حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ تصوف و سلوک تزکیہ نفس اور مشائخ علماء کرام کی رب العزت سے قربت وتعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض بزرگوں کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کام ہماری مشیت کے بغیر نہیں ہوتا تو عام لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگ حقیقت میں وہی چاہتے ہیں جو اللہ ربّ العزت کی چاہت و مشیت ہوتی ہے، اس لیے کچھ بھی ان مشائخ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔
اجتماع کا اختتام علامہ زاہد الراشدی صاحب کی دعا پر ہوا ۔ دعا کے بعد تمام شرکاء کی ضیافت کی گئی۔