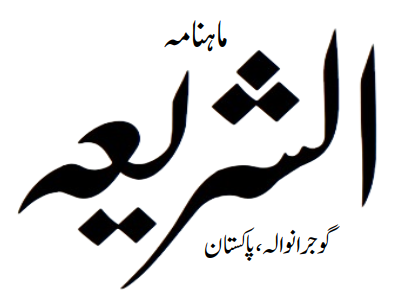مکی دور
چالیس سال کی عمر میں رسول اللہ ﷺ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو حکمِ الٰہی کے مطابق دعوت کے کام کا آغاز نہایت حکمت،تدبر اور تدریج کے ساتھ فرمایا۔آپ انے ابتداء اً ان لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی جو آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوچکے تھے اور آپ کے اخلاق او رچالیس سالہ زندگی کے شب وروز سے آگاہ تھے۔انہوں نے بلا تامل اس دعوت کو قبول کرلیا چنانچہ عورتوں میں حضرت خدیجہؓ ،مردوں میں حضرت ابوبکرؓ،غلاموں میں حضرت زیدؓ بن حارثہ اور بچوں میں حضرت علیؓ نے سب سے پہلے قبولیتِ اسلام کا شرف حاصل کیا۔
تیرہ سالہ مکی دور کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعوتِ دین کے لئے صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کی بھر پور معاونت کی اور اس ضمن میں پیش آنے والی ہر اذیت ،تکلیف اور دکھ کوبڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔دعوتِ دین کے اس مشکل اور کٹھن دور میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے جو مناہج اور اسالیب اختیار فرمائے، ذیل کی سطور میں ان کا ایک جائزہ پیش کیاجارہا ہے۔
انفرادی سطح پر دعوت / خفیہ دعوت
مکی دور میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے ہر فرد تک انفرادی سطح پر دعوت پہنچانے کا اسلوب اختیار کیا اوریہ حقیقت ہے کہ اگر افراد تک ذاتی سطح پر بات پہنچائی جائے تو اس کا یقیناًاثر ہوتا ہے ۔اس لئے اسوۂ رسول اکی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرامؓ نے بھی اس اندازِ دعوت کو بڑے مؤثر طریقۂ تبلیغ کے طور پر اپنایا۔ چنانچہ مکی دور کے ابتدائی سالوں میں کئی لوگوں کا صحابہ کرامؓ کی دعوت پر اسلام قبول کرنا اس طریقۂ تبلیغ کی کامیابی کی روشن دلیل ہے ۔علامہ ابن الاثیرؒ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:
’’ان(ابوبکرؓ) کے ہاتھ پر ایک جماعت جن کو ان کے ساتھ محبت وتعلق تھا، اسلام لائی۔یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں سے پانچ بزرگ بھی ان کے ہاتھ پر اسلام لائے‘‘۔ (۱)
حضرت عثمان بن عفانؓ کے تذکرہ میں ان بعض ناموں کی تفصیل بھی ملتی ہے جنہوں نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ۔نیز اشارۃً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدامیں یہ کامیابی انفرادی سطح پر خفیہ دعوت کی بدولت حاصل ہوئی:
’’قریش کے لوگ حضرت ابوبکرؓ کے پاس آتے تھے اور متعدد وجوہ مثلاً علم، تجربہ اور حسنِ مجالست کی بناء پر ان سے محبت کرتے تھے۔چنانچہ آنے والوں اور ساتھ بیٹھنے والوں میں سے جن لوگوں پر ان کو اعتماد تھا ان کوانہوں نے دعوتِ اسلام دی اور جیسا کہ مجھے معلوم ہواہے ان کے ہاتھ پر زبیر بن عوامؓ،عثمانؓ بن عفان اور طلحہؓ بن عبیداللہ اسلام لائے ‘‘۔ (۲)
حضرت ابوبکرؓ کو قریش میں جو مقام ومرتبہ حاصل تھا،جس کی بناء پر وہ قریش میں دعوت وتبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، ان کی اس حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں:
’’ابوبکرؓ اپنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے ،محبوب ،نرم اخلاق ،قریش میں بہترین نسب والے تھے،قریش کے انساب کا انہیں تمام قریش سے زیادہ علم تھا اور ان کی اچھائی برائی کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔تجارت کرتے تھے،خوش مزاج تھے، ہر ایک سے نیک سلوک کرتے تھے۔علم ،تجارت اور حسنِ معاملات کے سبب قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے، آپ نے قوم کے ان تمام افراد کو اسلام کی جانب بلانا شروع کردیا،جن پر آپ کو بھروسا تھاا ور جو کہ آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے تھے‘‘۔ (۳)
جن لوگوں نے حضرت ابوبکرؓ کی تبلیغ اور کوششوں سے اسلام قبول کیا ابنِ ہشام نے ان کے نام ذکر کئے ہیں جوحسبِ ذیل ہیں:
عثمانؓ بن عفان،زبیرؓ بن عوام، عبدالرحمنؓ بن عوف ،سعدؓ بن ابی وقاص ،طلحہؓ بن عبیداللہ ،ابو عبیدہؓ بن الجراح، ابو سلمہؓ، ارقمؓ بن ابی الارقم،عثمانؓ بن مظعون نیز ان کے دونوں بھائی قدامہؓ اور عبداللہؓ ،عبیدہؓ بن الحارث،سعیدؓ بن زید نیزان کی بیوی فاطمہ بنت الخطابؓ ،اسماء بنت ابی بکرؓ ،عائشہ بنت ابی بکرؓ،خبابؓ بن الارت، عمیرؓ بن ابی وقاص، عبداللہؓ بن مسعود،مسعودؓ بن القاری،مسعودؓ بن ربیعہ،سلیطؓ بن عمرو اور ان کے بھائی حاطبؓ ،عیاشؓ بن ربیعہ اور ان کی بیوی اسماءؓ بنت سلامہ،عامرؓ بن ربیعہ،عبداللہؓ بن حجش اور ان کے بھائی احمدؓ ،جعفرؓ بن ابی طالب اور ان کی زوجہ اسماءؓ بنت عمیس ،حاطبؓ بن الحارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت المجلل، خطابؓ بن الحارث اور ان کی بیوی فکیہہؓ بنت یسار،معمرؓ بن الحارث، السائبؓ بن عثمانؓ بن مظعون،المطلبؓ بن ازھراور ان کی بیوی رملہؓ بنت ابی عوف ،نعیمؓ بن عبداللہ1،عامرؓ بن فھیرہ مولیٰ ابی بکرؓ،خالدؓ بن سعید اور ان کی بیوی امینہؓ بنت خلف بن اسد ،حاطبؓ بن عمرو، ابو حذیفہؓ بن عتبہ بن ربیعہ، واقدؓ بن عبداللہ، خالدؓ ،عامرؓ،عافلؓ اور ایاسؓ بنو البکیر بن عبدیالیل میں سے،عمار بن یاسرؓ اور صہیبؓ بن سنان(۴)
دعوت وتبلیغ کے میدان میں صحابیات نے بھی،باوجود اپنی فطری کمزوریوں کے،صحابہ کرامؓ کے شانہ بشانہ کام کیا۔بعض صحابیات کے متعلق بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ ا نہوں نے انفرادی سطح پر دعوت وتبلیغ کاکام پوری جانفشانی سے کیا ۔ابن اثیر کی روایت کے مطابق حضرت ام شریکؓ دوسیہ ایک صحابیہ تھیں،جو آغاز اسلام میں مخفی طور پرقریش کی عورتوں کواسلام کی دعوت دیاکرتی تھیں۔قریش کو ان کی مخفی کوششوں کا حال معلوم ہوا تو ان کو مکہ سے نکال دیا۔(۵)
حضرت فاطمہ بنت خطابؓ کی استقامت ،عزم واستقلال اور دعوت سے متاثر ہوکر حضرت عمرؓ بن خطاب نے اسلام قبول کیا۔ (۶)
مدنی دور میں بھی صحابیات نے انفرادی سطح پر دعوت وتبلیغ کاکام انجام دیا۔حضرت ام حکیمؓ بنت الحارث کی شادی عکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی تھی۔ وہ خود تو فتح مکہ کے دن اسلام لائیں لیکن ان کے شوہر بھاگ کر یمن چلے گئے ابنِ شہاب بیان کرتے ہیں کہ ام حکیمؓ نے یمن کا سفر اختیار کیا اور ان (عکرمہؓ بن ابی جہل )کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ (۷)
حضرت ابو طلحہؓنے حالتِ کفر میں حضرت ام سلیمؓ کو پیغامِ نکاح دیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم کافر ہواور میں مسلمان ،نکاح کیونکر ہوسکتا ہے ۔ہاں اگر تم اسلام قبول کرلو تو وہی میرا مہر ہوگا ۔اس کے سوا تم سے کچھ طلب نہ کروں گی ۔ام سلیمؓ نے ابوطلحہؓ کے ضمیر کو جھنجھوڑ تے ہوئے اور ان کو مائل بہ اسلام کرتے ہوئے جو اسلوب اختیار فرمایا وہ ملاحظہ ہوچنانچہ آپؓ نے فرمایا:
یا ابا طلحہؓ! ألست تعلم ان الٰھک الذی تعبد نبت من الارض، قال: بلی، قالت: افلا تستحیی ان تعبد شجرۃ؟
’’اے ابو طلحہ! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا معبود زمین سے اگاہے؟ انہوں نے جواب دیا :ہاں،فرمایا: پھر تم کو درخت کی پوجا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟‘‘
بالآخر حضرت ام سلیمؓ کی ترغیب اور تبلیغ کے نتیجہ میں ابو طلحہؓ مسلمان ہوگئے اور اسلام ہی ان کا مہر قرار پایا۔ (۸)
حضرت عدیؓ بن حاتم اپنے قبیلے کے بادشاہ اور مذہباً عیسائی تھے۔ جب اسلامی فوجوں نے ان کے قبیلہ پر حملہ کیا تو یہ بھاگ کر شام چلے گئے۔ قیدیوں میں ان کی بہن سفانہؓ بنتِ حاتم بھی قیدی ہوکر آئیں اور رسول اللہ اکے حسنِ سلوک سے متاثر ہوکراسلام قبول کرلیا۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو اپنے خاندان میں واپس جانے کی اجازت دے دی۔چنانچہ یہ شام اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس آگئیں اور ان کواسلام کی طرف بلایا چنانچہ ان کی ترغیب سے عدیؓ اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ طیبہ حاضر ہوگئے اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرلی۔(۹)
اجتماعی سطح پر دعوت/علانیہ دعوت
مکی دور کے ابتدائی سالوں میں خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔جس میں صرف انفرادی سطح پر ہی دعوت ممکن تھی نتیجۃًکئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔بالآخر جب تبلیغ عام کایہ حکم نازل ہوا:
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِیْنَ (الحجر ، ۱۵:۹۴)
’’آپ کو جو حکم ملا ہے آپؐ وہ لوگوں کو سنادیں اور مشرکوں کی بالکل پروانہ کریں‘‘
تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی عوامی اجتماعات ،مجالس ،بازاروں ،میلوں اور دیگر تقریبات میں اجتماعی سطح پر لوگوں کو دعوت پیش کی اور اس راہ میں بے پناہ مشکلات کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کیا۔صحابہ کرامؓ میں سے یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیقؓ کوحاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اجتماعی سطح پر دعوت کا فریضہ سرانجام دیا ۔اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیقؓ اسلام میں سب سے پہلے خطیب اور اعلانیہ تبلیغ کرنے والے ہیں۔حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:
’’جب رسول اللہ اکے مرد صحابہ کی تعداد اڑتیس ہوگئی تو صدیقِ اکبرؓنے رسول اللہ ﷺ سے اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔آپ نے فرمایا:اے ابو بکرؓ!ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں،لیکن حضرت ابوبکرؓ اصرار کرتے رہے۔ جس پر رسول اللہ انے کھلم کھلا دعوت وتبلیغ کی اجازت دے دی۔چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ میں جاکر بیٹھ گیا اور حضرت ابوبکرؓلوگوں میں بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے جبکہ رسول اللہ ﷺ بھی تشریف فرماتھے۔حضرت صدیقِ اکبرؓاسلام میں سب سے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول ا کی طرف لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی۔مشرکین مکہ ابوبکرؓ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجدِ حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب ماراجبکہ حضرت ابوبکرؓ کو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے بھی روندا گیا‘‘۔ (۱۰)
ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالے سے روایت کرتے ہیں:
’’پہلا شخص جس نے رسول اللہ اکے بعد مکہ میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی وہ عبداللہؓ بن مسعود ہیں۔ایک روز رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓجمع ہوئے اور کہنے لگے کہ قریش نے قرآن کواپنے سامنے بلندآوازمیں پڑھتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ایساکون ہے جو انہیں قرآن سنائے؟عبداللہؓ بن مسعود نے کہا:میں (یہ کام انجام دیتا ہوں)سب نے کہا:ہمیں ان سے تمہارے لئے خوف ہے ۔ہم تو ایسا شخص چاہتے ہیں جو خاندان والا ہوکہ اگر ان لوگوں نے اس سے کوئی بدسلوکی کرنا چاہی تو اس کے اہلِ خاندان حفاظت کرسکیں۔ابنِ مسعودؓ نے کہا:مجھے چھوڑ دو اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائے گا۔دوسرے دن حضرت ابنِ مسعودؓمقامِ ابراہیم کے پاس ایسے وقت آئے جب قریش اپنی مجلسوں میں تھے۔پھر بلند آواز سے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ قریش نے اسے غور سے سنا اور بولے : ابن ام عبد نے کیا کہا؟ پھر خود ہی کہنے لگے یہ تو وہی پڑھتا ہے جو محمدا لایا ہے۔وہ سب کے سب ان کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اور ابنِ مسعود کے منہ پر مارنے لگے۔وہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اس سورۃ کے اس حصے تک پہنچ گئے ،جس تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔پھر اپنے ساتھیوں کی جانب لوٹ آئے کہ ان کے چہرے پر قریش نے نشانات ڈال دیئے تھے۔ابنِ مسعودؓ سے دوسرے صحابہؓ نے کہا:اسی چیز کا ہمیں ڈر تھا ،انہوں نے جواب دیا: آج دشمنانِ خدا میری نظرمیں جتنے ذلیل ہیں،اتنے ذلیل کبھی نہ تھے۔اگر تم چاہو تو اسی طرح ان کے پاس کل سویرے بھی پہنچوں ۔انہوں نے کہا: نہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے۔ تم نے انہیں وہ باتیں سنا دیں ،جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے‘‘۔(۱۱)
حضرت عبداللہ ابنِ عباسؓ نے حضرت ابوذر غفاریؓ کے قبولِ اسلام کی طویل روایت بیان کی ہے۔جب انہوں نے اسلام قبول کرلیاتو رسول اللہ ﷺ نے انہیں واپس اپنی قوم میں جانے اور تبلیغِ دین کا حکم دیا۔لیکن حضرت ابوذرؓ نے بڑے جوش اور جذبۂ جان نثاری کے ساتھ بارگاہِ رسالت میں عرض کیا:
والذی نفسی بیدہ لاصرخن بھا بین ظہر انیھم۔
’’اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے میں اس کلمۂ توحید کا اعلان کافروں میں پورے زور سے کروں گا‘‘۔
چنانچہ حضرت ابوذرغفاریؓ بیت اللہ میں آئے اور لوگوں کو اللہ ورسول کی طرف دعوت دی۔مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹادیااتنے میں حضرت عباسؓ آگئے اور وہ ان کو بچانے کیلئے ان پر لیٹ گئے اور ان کو کافروں سے چھڑایا۔ اگلے دن حضرت ابوذر غفاریؓنے پھران کو ویسے ہی سرعام اور اعلانیہ دعوتِ اسلام دی۔ اس روز بھی کافروں نے ان کو خوب مارا چنانچہ حضرت عباسؓ کی مداخلت ہی سے ان کی جان بچی۔(۱۲)
ایک دفعہ حضرت عثمانؓ بن مظعون قریش کی ایک ایسی مجلس میں تشریف لے گئے جس میں لبیدؓ بن ربیعہ2 شعر کہہ رہا تھا جب اس نے یہ شعر پڑھا:
الا کل شیء ماخلا اللّٰہ باطل
’’خبردار !اللہ کے سوا سب چیزیں باطل ہیں‘‘
تو آپؓ نے اس کو خوب داد دی اور فرمایا:تم نے سچ کہا ہے۔لیکن جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا
’’اور ہر نعمت کو بالآخر زوال ہے‘‘
تو حضرت عثمانؓ بن مظعون نے اس کی بھر پور تردید کی اور فرمایا: تم جھوٹے ہو اس لئے کہ جنت کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔
مشرکین نے گھورکر حضرت عثمانؓ بن مظعون کی طرف دیکھا اور لبید سے کہا تم یہ شعر پھر پڑھو۔ لبید نے پھر پڑھا ۔آپ نے پھر اسی طرح پہلے مصرع کی تصدیق اور دوسرے کی تکذیب کی۔اہلِ مجلس میں سے ایک احمق شخص اٹھا اور ان پر حملہ کردیا ،ان کو مارا یہاں تک کہ ان کی ایک آنکھ نیلی ہوگئی۔ لیکن وہ اپنا فریضۂ تبلیغ پورا کرچکے تھے۔(۱۳)
مکی دور میں تو صحابیات کے حوالے سے کوئی ایسی روایت معلوم نہیں ہوسکی جس سے معلوم ہوکہ انہوں نے اجتماعی سطح پر دعوت کا کام کیا ہو،تاہم مدنی دور میں صحابیات نے بھی اجتماعی سطح پر دعوتِ دین کی خدمات انجام دیں۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی اس روایت میں ملتی ہے کہ ایک غزوہ میں صحابہ کرامؓ پانی کی تلاش میں نکلے تو حسنِ اتفاق سے ایک عورت سے ملاقات ہوگئی جو ایک اونٹ پر سوار تھی اور اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔صحابہؓ نے اس سے پانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ پانی یہاں سے ایک دن کی مسافت پر ہے چنانچہ صحابہ کرامؓ اس کو رسول اللہ اکی خدمت میں لے آئے۔صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے پانی استعمال کیا معجزانہ طور پر پانی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی ۔اس عورت نے جب رسول اللہ ﷺ کے اس معجزہ کو دیکھا تو اس کو اسی وقت آپ ا کی حقانیت کا یقین ہوگیا۔ واپسی پر رسول اللہ ﷺ نے اس کو پانی کی قیمت دلوادی جس سے وہ عورت آپ ا کے حسنِ اخلاق سے بہت متاثر ہوئی چنانچہ جب یہ عورت واپس اپنے قبیلے میں گئی تو اس نے نہ صرف اپنے اسلام کا اعلان کیا بلکہ تمام قبیلہ والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی چنانچہ تمام لوگوں نے اس کی دعوت پر اسلام قبول کرلیا۔ (۱۴)
ہجرتِ حبشہ3 اور دعوتِ دین کا فروغ
جب رسول اللہؐ نے ملا حظہ فرمایا کہ خودآپ اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق اور اپنے چچا ابو طالب کی بدولت آفتوں سے محفوظ ہیں جبکہ آپ کے اصحاب مصائب وآلام کا نشانہ بن رہے ہیں نیز آپ کفار مکہ سے اپنے اصحاب کی حفاظت کرنے سے بھی قاصر ہیں تو ایک دن آپ ﷺنے صحابہ سے مخاطب ہوکر فرمایا:
لوخر جتم الی ارض الحبشۃ فان بھا ملکا لایظلم عندہ احد،وھی ارض صدق ،حتی یجعل اللّٰہ لکم فرجا مما انتم فیہ (۱۵)
’’اگر تم لوگ سرزمینِ حبشہ ہجرت کرجاؤ (تو تمہارے لئے بہترہے کیونکہ) وہاں کے بادشاہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی والی سرزمین ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ان آفتوں سے، جن میں تم مبتلاء ہو ،کوئی کشائش پیدا فرمادے‘‘۔
چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے اہل ایمان نے ماہ رجب 5 نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ (۱۶) اول اول گیارہ مردوں اور چار عورتوں نے شرفِ ہجرت حاصل کیا۔حضرت عثمانؓ بن عفان،زبیر بن العوامؓ،مصعبؓ بن عمیر،عبدالرحمنؓ بن عوف،ابوسلمہؓ بن عبدالاسد،عثمانؓ بن مظعون،عامرؓ بن ربیعہ،ابوسبرہؓ بن ابی رہم یا ابو حاطبؓ بن عمرو،سہیلؓ بن بیضاء، عبداللہؓ بن مسعود،ابو حذیفہؓ بن عتبہ،اور چار خواتین یہ ہیں۔ رقیہ بنتِ رسول اللہ ﷺزوجہ عثمانِ غنیؓ،سہلہؓبنتِ سہیل زوجہ ابوحذیفہؓ،سلمہؓبنتِ ابی امیہ زوجہ ابوسلمہؓاور لیلیٰؓ بنتِ حشمہ زوجہ عامرؓ بن ربیعہ۔(۱۷)
یہ حضرات حبشہ میں بڑی پرسکون زندگی بسر کررہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ قریش نے اسلام قبول کرلیا ہے چنانچہ یہ لوگ مکہ واپس آگئے ۔یہاں پہنچنے پر معلوم ہواکہ قریش تو پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں ۔اس لئے کچھ لوگ حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ مکہ ہی میں ٹھہر گئے ۔اب یہ حضرات پہلے سے بھی زیادہ قریش کے ظلم وستم کا نشانہ بنے چنانچہ رسول اللہ انے دوبارہ انہیں حبشہ کی طرف ہجر ت کرنے کی اجازت دی۔اس بار تراسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں نے ہجرت کی۔(۱۸)
مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ پچاس مہاجرین کا ایک جتھہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔حضرت ابوموسیٰ اشعریؓکا بیان ہے:
’’ہم یمن میں تھے ہمیں اطلاع ملی کہ نبی کریم امکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ہم وہاں سے کشتیوں میں سوار ہوکر روانہ ہوئے تاکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں شرفِ باریابی حاصل کریں۔لیکن راستہ میں ہمیں سمندری طوفان نے آلیااور ہماری کشتیاں حبشہ کے ساحل پر جالگیں ۔وہاں ہماری ملاقات جعفرؓ بن ابی طالب سے ہوئی چنانچہ ہم نے وہیں اقامت اختیار کرلی اور کئی سال وہاں قیام کیا۔ ہم اس وقت حضرت جعفرؓ کی معیت میں مدینہ واپس آئے جب کہ خیبر میں سارے قلعے فتح ہوچکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرارہا تھا۔ہمیں دیکھ کر رسول اللہ انے فرمایا:
لکم انتم یااہل السفینۃ ہجرتان (۱۹)
’’اے کشتی والو!تمہیں دو ہجرتوں کا ثواب ملے گا‘‘۔
یعنی پہلی ہجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف۔
ابنِ قیم کا بیان ہے کہ جب مہاجرین حبشہ کو رسول اللہؐ کی ہجرتِ مدینہ کی اطلاع ملی تو ان میں سے تینتیس آدمی واپس آگئے ۔جن میں سے سات کو راستہ ہی میں کفارِ مکہ نے گرفتار کرلیااور باقی بخیریت مدینہ رسول اللہؐ کی خدمت میں پہنچ گئے۔اس کے بعد باقی مہاجرین فتح خیبر کے سال ۷ ھ میں واپس آئے۔(۲۰) ابنِ ہشام نے بڑی تفصیل سے مہاجرین حبشہ کا ذکر کیا ہے اور قبائل کے اعتبار سے مہاجرین حبشہ کی تفصیل بیان کی ہے۔نجاشی کی بدولت مسلمان حبشہ میں امن وامان سے زندگی بسر کرنے لگے ۔قریش کو بھلا کب گواراتھا کہ مسلمان سکھ اور چین کی زندگی بسر کرنے لگیں،چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو اور ان کو ہمارے حوالے کردو۔چنانچہ کفارِمکہ نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو اس مقصد کیلئے منتخب کیا۔جنہوں نے نجاشی سے قبل اس کے درباریوں سے ملاقات کی اور ان کو قیمتی تحائف دے کر اپنی حمایت پر آمادہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ کل دربار میں ہماری تائید کریں۔دوسرے دن سفرائے قریش نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کئے جائیں ،درباریوں نے بھی بھرپور تائید کی۔نجاشی نے مسلمانوں کو بلابھیجااور کہا کہ تم لوگوں نے کون سا دین ایجاد کرلیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے۔معاملہ چونکہ بڑا نازک اور تشویش ناک تھا اسلئے تمام صحابہؓ نے باہم مشورہ کیا کہ نجاشی سے کس انداز سے بات کی جائے۔ بالآخر تمام صحابہؓ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا:
واللّٰہ ماعلمنا،وما امرنا بہ نبینا کائنًا فی ذالک ماھوکائن (۲۱)
’’اللہ کی قسم!ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جن باتوں کا آپؐ نے ہمیں حکم دیا ہے۔اس معاملہ میں جو ہوتا ہے ہوجائے‘‘۔
چنانچہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کیلئے حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کاانتخاب کیا۔جنہوں نے نجاشی کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
ایھا الملک! کنا قوما اہل جاہلیۃ، نعبد الاصنام، ونأکل المیتۃ، ونأتی الفواحش، ونقطع الارحام، ونسئی الجوار، ویأکل القوی منا الضعیف، فکنا علی ذالک حتی بعث اللّٰہ الینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، فدعانا الی اللّٰہ لنوّحدہ ونعبدہ ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونہ من الحجارۃ والاوثان و أمرنا بصدق الحدیث وأداء الامانۃ، وصلۃ الرحم، وحسن الجوار، والکف عن المحارم والدماء، ونھانا عن الفواحش، وقول الزور، وأکل مال الیتیم، وقذف المحصنات، وأمرنا ان نعبداللّٰہ وحدہ لانشرک بہ شیئا، وأمرنا بالصلوٰۃ والزکوٰۃ والصیام، فصدّقناہ وآمنّا بہ‘‘(۲۲)
’’اے بادشاہ!ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے،بت پوجتے اور مردار کھاتے تھے،بد کاریاں کرتے تھے،ہمسائیوں کو ستاتے تھے ،بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا،قوی لوگ کمزور کوکھا جاتے تھے،اسی اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق ودیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑدیں،سچ بولیں،خون ریزی سے باز آجائیں،یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسائیوں کوآرام دیں، عفیف عورتوں پربدنامی کا داغ نہ لگائیں،نماز پڑھیں،روزے رکھیں،زکوٰۃ دیں،پس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے‘‘۔
اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آجائیں۔نجاشی نے کہا!جو کلام الٰہی تمہارے رسول پر اترا ہے ،کہیں سے پڑھو۔حضرت جعفرؓنے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کیں،نجاشی پر رقت طاری ہوگئی یہاں تک کہ اس کی داڑھی تربتر ہوگئی ۔جب نجاشی کے پاس موجود علماء نے یہ کلام سنا تو وہ بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے بھیگ گئے ۔پھر کہا اللہ کی قسم !یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں،یہ کہہ کر سفراء قریش سے کہا: تم واپس جاؤ۔میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔
دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا : جنابِ والا !آپ کو یہ بھی معلوم ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟نجاشی نے ایک بار پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔مسلمانوں کو اب حقیقی فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر حضرت عیسیٰ ؑ کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے ،وہ ناراض ہوگا۔تاہم صحابہ کرامؓنے متفقہ طور پر فیصلہ کیا:
نقول واللّٰہ ماقال اللّٰہ،وماجاء نا بہ نبینا‘(۲۳)
’’قسم خدا کی!ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا حکم اور رسول اللہؐ کی تعلیم ہے‘‘۔
جب یہ لوگ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو نجاشی نے کہا:تم لوگ حضرت عیسیٰ ؑ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفرؓنے فرمایا: ہمارے نبی ا نے ہمیں بتایا ہے:
ھو عبداللّٰہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاھا الی مریم العذراء البتول
’’عیسیٰ ؑ اللہ کے بندے ،رسول،اس کی روح اور کلمہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور پاکباز مریم کی طرف ڈال دیا‘‘۔
نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا :واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ ؑ اس ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔دربار میں موجود عیسائی علماء نجاشی کے طرزِ عمل سے سخت برہم ہوئے 4 تاہم نجاشی نے ان کے غصہ کی قطعاً پرواہ نہ کی۔قریش کے سفیر بالکل ناکام واپس آئے۔(۲۴)
حبشہ میں صحابہ کرامؓ نے دعوتِ دین کے لئے جو اسلوب اختیار کیااس کی ایک ہلکی سی جھلک حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کی اس معرکۃ الآراء تقریر میں دیکھی جاسکتی ہے ۔حضرت جعفرؓنے اپنے مخاطب نجاشی اور دیگر امراء کے مقام ومرتبہ کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوئے اتنے مدلل،خوبصورت اور دلنشیں پیرائے میں اپنی دعوت کو پیش کیا کہ نہ صرف قریشی سفیر اپنے مشن میں مکمل طور پر ناکام ہوئے بلکہ سرزمینِ حبشہ میں مسلمانوں کے لئے حالات مزید سازگار ہوگئے۔حضرت جعفرؓکی حق وصداقت پر مبنی گفتگو سے نجاشی اور اس کے درباری اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔
حضرت جعفرؓ کی اس تقریر سے اس وقت تک کے نصابِ دعوت کا بھی اندازہ کیاجاسکتاہے۔یقیناًحبشہ میں مسلمان توحیدو رسالت کے علاوہ ان ہی اخلاقی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہوں گے۔جن کا ذکر حضرت جعفرؓنے اپنی تقریر میں فرمایا۔حبشہ میں مسلمانوں کے اسلوبِ دعوت کا یہ پہلو بھی خصوصیت سے قابلِ ذکر ہے کہ مشکل ترین لمحات میں انہوں نے بنیادی عقائد پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا اور اس معاملہ میں بڑا واضح اور دو ٹوک مؤقف اختیار کیا۔مسلمانوں کے اسی اسلوبِ دعوت کی بنا پر نہ صرف نجاشی بلکہ کئی دیگر لوگوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔مہاجرینِ حبشہ کی بدولت دعوتِ اسلام حبشہ میں اس قدر عام ہوئی کہ اس سے نہ صرف بادشاہ بلکہ اس کے درباری بھی متاثرہوئے۔ملکِ حبشہ کے عیسائیوں نے بھی اسلام کی تعلیمات سے آگاہی کی کوششیں شروع کردیں۔اس بات کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ وہاں سے بیس عیسائیوں کاایک وفد مکہ آکر رسول اللہ اسے ملا۔رسول اللہ ﷺ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور وہ ایمان لے آئے۔(۲۵)
حبشہ میں مسلمانوں کی دیگر دعوتی سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں؟ یہ معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تاہم یہ طے شدہ بات ہے کہ صحابہ کرامؓنے حبشہ کی پرامن فضا اور سازگار ماحول سے ضرور استفادہ کیاہوگا۔ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں:
’’اب چونکہ تبلیغ کی آزادی تھی،اس لئے یہ مسلمان (مکے کے نومسلم مہاجر)حبشہ میں تبلیغ کرنے لگے۔نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں میں وہاں کافی تعداد میں یعنی کم ازکم چالیس پچاس حبشی مسلمان ہوگئے‘‘۔(۲۶)
نجاشی کا قبولِ اسلام اس حقیقت کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ حبشہ میں مسلمانوں نے دعوتِ حق کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہوگا ۔جب نجاشی کے انتقال کی خبرمدینہ پہنچی تو اس پر ر سول اللہؐ نے غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھی۔ (۲۷)
جب رسول اللہؐ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے جبکہ جو لوگ وہاں رہ گئے تھے ان کو واپس لانے کیلئے رسول اللہ ﷺ نے عمروؓ بن امیہ الضمری کو ایک خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔رسو ل اللہ ا کے خط کے جواب میں نجاشی نے لکھا:
’’امابعد!فقد ارسلت الیک یارسول اللّٰہﷺ من کان عندی من اصحابک المہاجرین من مکۃالی بلادی،وہااناارسلت الیک ابنی اریحا فی ستین رجلاً من اہل الحبشۃ‘ (۲۸)
’’اے اللہ کے رسول ! مہاجرین مکہ میں سے جو لوگ میرے پاس آئے تھے انہیں میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اور میں آپ کی طرف اہلِ حبشہ میں سے بھی ساٹھ افراد کو اپنے بیٹے اریحا سمیت بھیج رہا ہوں‘‘۔
حبشہ میں مسلمانوں کی دعوتی سرگرمیوں کے حوالے سے یہاں پر ایک روایت کاذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جس سے واضح طور پر یہ اشارات ملتے ہیں کہ صرف مہاجر ین حبشہ ہی نہیں بلکہ دیگر حبشی مسلمان بھی قبول اسلام کے بعد دعوت کاکام کسی نہ کسی سطح پر کرتے رہے ہیں۔ابن ہشام کی روایت کے مطابق جب رسول اللہؐ نے عمروؓ بن امیہ الضمری کومہاجرین حبشہ کو لانے کے لئے نجاشی کے پاس بھیجا تو اتفاق سے عمروؓ بن العاص،جو حبشہ آئے ہوئے تھے،نے عمرو بن امیہ کونجاشی کے دربار سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو عمرو بن العاص فوراً نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: جو شخص ابھی ابھی آپ کے دربار سے نکل کر گیاہے یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے قتل کردوں۔نجاشی یہ سن کر انتہائی غضبناک ہوا اور کہا:
’’أتسألنی ان أعطیک رسول رجل یأتیہ الناموس الاکبر الذی کان یاتی موسیٰ لتقلہ ! قال : قلت ! ایھا الملک ، أکذاک ھو ؟ قال : ویحک یاعمرو ! اطعنی واتبعہ ، فانہ واللّٰہ لعلی الحق ، ولیظھرن علی من خالفہ ،کما ظھر موسیٰ علی فرعون وجنودہ، قال ، قلت : افتبا یعنی لہ علی الاسلام؟ قال: نعم، فبسط یدہ، فبایعتہ علی الاسلام۔ (۲۹)
’’کیاتم مجھ سے قتل کرنے کیلئے ایسے انسان کے قاصد کو حوالے کرنے کی درخواست کرتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پرآتا تھا؟ اس پر عمرو بن العاص نے عرض کیا:اے بادشاہ!کیایہ معاملہ ہے؟نجاشی نے کہا :اے عمرو تیرا برا ہو!میری مان اور جاکر ان کی اتباع کرلو۔خدا کی قسم ! وہ بالکل حق پر ہیں،جس طرح موسیٰ ،فرعون اور اس کی افواج پر غالب آئے تھے ٹھیک اسی طرح یہ بھی ان تمام لوگوں پر غالب آئیں گے جو انکے مخالف ہیں۔( اب حق عمرو بن عاص پر واضح ہوچکا تھا)کہنے لگے!کیا آپ ان کی جانب سے اسلام پر میری بیعت لیں گے؟چنانچہ نجاشی نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرلی۔
چنانچہ حضرت عمرو بن العاص نے نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اورواپس مکہ پلٹ گئے ۔ کچھ عرصہ تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، تاہم فتح مکہ سے قبل بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکر اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔(۳۰)
اس روایت سے یہ بات بہرحال واضح ہوجاتی ہے کہ حبشہ میں فروغِ اسلام میں مہاجرین کی کوشش کے علاوہ نجاشی اور دیگر حبشی مسلمانوں کے اثر ورسوخ نے بھی نمایاں کردار اد اکیاہوگا۔اس لئے یہ کہنا بجا طور پر درست ہے کہ حبشہ میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف وہی نہ تھی جو حضرت جعفرؓ کی معیت میں مدینہ حاضر ہوئے بلکہ یہ تعداد یقیناًاس سے کہیں زیادہ ہوگی اور کتنے ہی نومسلم وہ ہوں گے جو اپنی مجبوریوں کے باعث مدینہ حاضری سے قاصر رہے۔
چنانچہ حضرت جعفرؓ بن ابی طالب ۷ھ فتح خیبر کے موقع پر باقی ماندہ مسلمانوں کے ساتھ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وفد میں وہ حبشی مسلمان بھی شامل تھے جو مہاجرین حبشہ کی دعوت سے متاثر ہوکراسلام قبول کرچکے تھے اور اب رسول اللہؐ کی زیارت کاشرف حاصل کرنے کیلئے حاضر ہوئے تھے۔ان حبشی مسلمانوں میں سے بعض کے نام کتب رجال اور سیر کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔
حبشی مسلمانوں میں نجاشی کے بیٹے اریحا کے علاوہ اس کے دو بھتیجوں ذودجن اور ذومخبر کے نام بھی ملتے ہیں۔(۳۱)ابنِ اثیر نے حضرت ابرہہؓ کے تذکرہ میں بھی آٹھ حبشی مسلمانوں کے نام گنوائے ہیں جو یہ ہیں بحیراؓ،ابرہہؓ،اشرفؓ،ادریسؓ،ایمنؓ،نافعؓ اور تمیمؓ(۳۲)اس کے علاوہ حضرت تمامؓ،دریدالراہبؓ،ذومہدمؓ ،ذو مناحبؓ اور عامرالشامیؓ کے نام بھی ملتے ہیں۔(۳۳)
قبائل عرب کے لئے مبلغین کا تقرر
ابتداء میں رسول اللہ ااور صحابہ کرامؓ کی تبلیغی ودعوتی سرگرمیوں کا مرکز زیادہ تر مکہ اور اس کی نواحی بستیاں ہی تھیں جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
وَکَذٰلِکَ اَوْحَیْنَآ اِلَیْکَ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَھَا وَتُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیْہِ ( الشوریٰ، ۴۲:۷)
’’اور اس طرح ہم نے وحی کے ذریعے عربی زبان میں قرآن اتارا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے قرب وجوار میں رہنے والوں کو ڈرائیں اورانہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے‘‘۔
لیکن جب قریش مکہ کی طرف سے اسلام کی مخالفت میں مسلسل تیزی اور شدت آنے لگی تو آپ نے دیگر قبائل عرب کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کافیصلہ کیا۔دیگر قبائل میں دعوت وتبلیغ کے سلسلہ میں صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کی بھر پور معاونت کی چنانچہ رسول اللہ ﷺ جس قبیلہ میں بھی دعوت وتبلیغ کے لئے تشریف لے گئے ،صحابہ کرامؓ آپ کے ہمراہ رہے۔بالخصوص حضرت صدیق اکبرؓ ،زیدؓ بن حارثہ اور علی المرتضیؓآپ کے دوش بدوش نظر آتے ہیں۔
عبداللہؓ بن مسعود قبولِ اسلام سے قبل اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیقؓ میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے دودھ طلب کیا ۔میں نے عرض کیا:مجھے امانت داربنایاگیاہے(یعنی مجھے دینے کا اختیار نہیں)تو آپ نے فرمایا:تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی تک حاملہ نہ ہوئی ہو ؟ میں نے ایک ایسی ہی بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو دودھ اتر آیا،آپ نے خود ودھ دوہا،خود پیا اور ابو بکرؓ کوبھی پلایا،پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا تو دودھ خشک ہوگیا۔میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول مجھے بھی یہ چیز سکھادیں۔آپ نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا:
یرحمک اللّٰہ فانک علیم معلم(۳۴)
’’اللہ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے۔تم تعلیم یافتہ نوجوان ہو‘‘۔
اس حدیث سے معلوم ہوتاہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ سے باہر کسی دوردراز مقام سے واپس لوٹ رہے تھے ،جہاں آپ ا یقیناًدعوت وتبلیغ کے سلسلہ ہی میں تشریف لے گئے ہوں گے،اور ابوبکرؓ اس دعوتی مشن میں آپ ا کے ہمراہ تھے۔سفر کی طوالت کے باعث ہی آپ انے پیاس کی شدت کے ہاتھوں مجبور ہوکر عبداللہؓ بن مسعود سے دودھ طلب فرمایاہوگا۔
بعض روایات میں مزید وضاحت ملتی ہے کہ اس نوعیت کی مہمات میں نہ صرف صدیق اکبرؓ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ہوتے تھے بلکہ لوگوں سے آپ کا تعارف بھی کرواتے تھے۔حضرت علیؓکا بیان ہے :
’’اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ ﷺ کو قبائل عرب کو دعوت دینے کاحکم دیا تو رسول اللہؐ دعو ت وتبلیغ کے لیے نکل پڑے اور ابوبکر صدیقؓ آپ کے ہمراہ تھے۔مختلف قبائل کی قیام گاہوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک مجلس میں پہنچے جس پر سکون اوروقار کے آثار نمایاں تھے۔ابوبکر صدیقؓ آگے بڑھے اور انہیں سلام کیا اور ابوبکرؓ نیکی کے ہرکام میں سبقت کرنے والے تھے۔ابوبکر صدیقؓ نے ان سے پوچھا: آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہم بنی شیبان بن ثعلبہ میں سے ہیں ۔تو آپؓنے فرمایا: غالباً آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ یہاں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں۔اور پھر رسول اللہؐ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:وہ یہی ہیں ۔اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔‘‘(۳۵)
عبداللہ بن والصبہ العبسی اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں: ہم جمرۃ الاولیٰ کے سامنے منی میں خیمہ زن تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ رسول اللہ ﷺ اونٹنی پر سوار تھے اور زیدؓ بن حارثہ آپ اکے پیچھے سوار تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دعوتِ اسلام دی۔ (۳۶)
اسی طرح جس وقت رسول اللہ ﷺ اہل طائف کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی حضرت زید بن حارثہؓ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔(۳۷)
ان چند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اجہاں کہیں بھی دعوتی وتبلیغی مشن پر جاتے تو صدیق اکبرؓ اور زید ؓ بن حارثہ کے علاوہ حضرت علیؓ باوجود اپنی طفولیت کے آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔
مکی دور میں بعض قبائل کی طرف رسول اللہؐ نے دعوت وتبلیغ کیلئے صحابہ کرامؓ کوروانہ فرمایا۔رسول اللہؐ کی پوری دعوتی زندگی کا یہ اصول رہا ہے کہ جو شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوجاتا،آپ اسے اس کے قبیلے ،خاندان اور افرادِ خانہ کے لئے مبلغ مقرر فرمادیتے تھے۔ خصوصاًمکی دور میں اسلام کی جس قدر اشاعت ہوئی اس میں انفرادی دعوت کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔
ذیل کی سطور میں ان صحابہ کرامؓ کی دعوتی سرگرمیوں کا حال بیان کیاجارہاہے جن کورسول اللہ ﷺ نے ہجرت سے قبل اپنے اپنے قبائل میں دعوت وتبلیغ کے لئے روانہ فرمایا۔
ابو موسیٰ اشعریؓ کا قبولِ اسلام اور دعوتِ اسلام
ابن الاثیرکا بیان ہے کہ ابوموسیٰ الاشعریؓ قدیم الاسلام صحابی تھے جنہوں نے مکہ حاضر ہوکر اسلام قبول کیا۔(۳۸)
حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی قوم کے کثیر لوگوں نے ان کے زیرِ اثر اسلام قبول کیا۔چنانچہ ابوموسیٰ اشعریؓکااپنا بیان ہے کہ جب ہمیں یمن میں اطلاع ملی کہ رسو ل اللہ ا مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو میں اپنی قوم کے پچاس آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوا تاکہ ہم بارگاہِ رسالت میں شرفِ بازیابی حاصل کریں لیکن سمندری طوفان ہمیں حبشہ لے گیا جہاں سے ہم حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کے ہمراہ واپس آئے اور اس وقت خیبر کے سارے قلعے فتح ہوچکے تھے۔(۳۹)
اس روایت سے معلوم ہوتاہے کہ مکہ میں رسول اللہ اکے ہاتھ پر قبولِ اسلام کے بعد حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ واپس اپنے قبیلے میں جاکر مسلسل دعوت وتبلیغ میں مصروف رہے ہوں گے اور آپؓ کی کوششوں سے اسلام قبول کرنے والوں کی کثرت کااندازہ اس سے لگایا جاسکتاہے کہ صرف پچاس افراد تو وہ تھے جو مدینہ کے ارادہ سے آپؓکے ساتھ آئے۔
ضمادؓ ازدی کا قبولِ اسلام اور دعوتِ اسلام
ازد شنوء ۃ ،عرب کے نامور قبیلوں میں سے ایک مشہور قبیلہ تھااس کے ایک رئیس ضمادؓ ازدی مکہ مکرمہ آئے وہ ان مریضوں کو دم کرتے تھے جنہیں آسیب یا جنات کی تکلیف ہوتی تھی۔اسے یہاں کے چند احمقوں نے رسول اللہ اکے بارے میں بتایا کہ انہیں آسیب کی شکایت ہے،وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، انہیں غشی کے دورے پڑتے ہیں ۔علاوہ ازیں ایک نئے مذہب کا پروپیگنڈا بھی بڑے زور وشور سے کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے سارے شہر میں فتنہ وفساد کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں ۔ایسے بیماروں کے لئے تیرا دم بڑا اکسیر ہے۔اگر تم ان کو دم کردو تو تیرے دم سے وہ صحت یاب ہوجائیں گے ،اس طرح تمام قوم تیری شکر گزار ہوگی۔انہوں نے دل میں طے کیا کہ اگر میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو میں ضرور اسے دم کروں گا ،شائد اللہ تعالیٰ اسے میرے ذریعہ شفایاب کردے۔چنانچہ اس نے ایک روز رسول اللہ ﷺ کوحرم کے صحن میں بیٹھے دیکھا۔ وہ حضو راکے پاس جاکر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میرے پاس آسیب کا بڑا مجرب دم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے میرے دم سے صحت بخش دیتاہے۔ کیاآپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کو دم کروں؟اس کی بات سن کر رسول اللہؐ یوں گویا ہوئے:
’’ان الحمد للّٰہ،نحمدہ ونستعینہ من یھدی اللّٰہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ھادی لہ واشھد ان لاالہ الا اللّٰہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ‘‘
ضماد ؓ یہ کلمات سن کر بے خود ہوگئے اور عرض کی ایک بار پھر دہرائیے ۔رسول اللہ انے تین بار ان کلمات کو دہرایا۔انہیں سننے کے بعد ضمادؓ کہنے لگے:
لقد سمعت قول الکھنۃ،وقول السحرۃ،وقول الشعراء، فما سمعت مثل کلماتک ھٰولآء، ھات یدک ابا یعک علی الاسلام۔
’’میں نے کاہنوں اور جادوگروں کے اقوال سنے ہیں،شعراء کے اشعار سنے ہیں لیکن میں نے آپ کے ان کلمات کی مثل کوئی کلام نہیں سنا۔ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں‘‘۔
رسول اللہ ﷺ نے اپنا دستِ اقدس بڑھایا ان سے بیعت لی اور پھرفرمایا : یہ بیعت صرف تمہاری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری قوم کی طرف سے بھی ہے۔انہوں نے کہا بیشک یہ بیعت میری قوم کی طرف سے بھی قبول فرمائیں۔(۴۰)
بعدکے دور میں رسول اللہ انے ایک لشکر بھیجا جس کا گزر قومِ ضمادؓ پرہوا۔ امیرلشکر نے پوچھا : کیاتم میں کسی نے اس قوم سے کچھ لیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا!ہاں،میں نے ایک لوٹا لیاہے۔امیرِ لشکرنے کہا واپس کردو،یہ حضرت ضمادؓ کی قوم ہے۔(۴۱)
اس روایت سے بالجملہ یہ معلوم ہوتاہے کہ حضرت ضما دؓکی قوم ان کے زیرِ اثر اسلام قبول کرچکی تھی اور یہ چیز صحابہ کرامؓکے علم میں تھی۔اس لئے امیرِِ لشکر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چونکہ یہ حضرت ضمادؓ کی قوم ہے جو مسلمان ہوچکی ہے اور مسلمان کا مال لوٹنا جائز نہیں اس لئے ان کا مال واپس کردیاجائے۔
طفیلؓ بن عمرو کی دعوتِ اسلام
حضرت طفیلؓ بن عمروالدوسی ہجرت سے قبل بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے تو دل پہلے ہی نورِ ایمان سے لبریز ہوچکا تھا۔قبولِ اسلام کے بعد خود ہی عرض کیا کہ یارسول اللہ ، میر ی قوم میں میری چلتی ہے میں ان کے پاس جاکر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا۔چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اپنی قوم کی طرف مبلغ بنا کرروانہ فرمایا۔حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہؐ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت طفیلؓ بن عمرو نے بھی اپنی قوم کے ایک مہاجر کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ (۴۲)
اس روایت سے فی الجملہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اثرسے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن ابن ہشام اور ابن الاثیر کی روایت ہے کہ حضرت طفیلؓ بن عمرو دوسی خدمتِ اقدس سے پلٹ کر مسلسل اشاعتِ اسلام کی خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ ﷺنے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو انہوں نے بھی قبیلہ دوس کے ستر یا اسی گھرانوں کے ساتھ شرفِ ہجرت حاصل کیا اور یہ تمام لوگ ان ہی کے زیرِ اثر مسلمان ہوئے تھے۔(۴۳) دوس کا وفد بارگاہِ رسالت میں ۷ ھ میں حاضر ہوا۔(۴۴)
ابو ذر غفاریؓ کی قبیلہ غفار کو دعوت
حضرت ابوذر غفاریؓ فطرتاً نیک سیرت انسان تھے ۔جب رسول اللہؐ کی بعثت کی خبر سنی تو بارگاہِ نبوی امیں حاضر ہوکر حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔رسول اللہ انے ان سے فرمایا:
فھل انت مبلغ عنی قومک ؟ عسی اللّٰہ ان ینفعھم بک ویأجرک فیھم(۴۵)
’’کیا تم میری طرف سے اپنی قوم کو اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ شاید تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نفع دے اور تمہیں اجرو ثواب عطافرمائے‘‘۔
چنانچہ واپسی پر حضرت ابوذر غفاریؓ نے سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو دعوتِ اسلام دی۔وہ مسلمان ہوگئے ۔اس کے بعد ماں کو مائل بہ اسلام کیاوہ بھی بخوشی حلقۂ اسلام میں داخل ہوگئیں ۔پھرِ آپؓ نے تمام قوم کو اسلام کی طرف بلایا ۔نصف لوگ اسی وقت مسلمان ہوگئے اور باقی نے بھی ہجرت کے بعد اسلام قبو ل کرلیا۔حضرت ا بو ذرؓ کی دعوتی سرگرمیوں نے دوسرے قبائل کو بھی متاثر کیا چنانچہ قبیلہ غفار کے متصل ہی بنو اسلم کا قبیلہ آباد تھا۔ وہ لوگ بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ!جس چیز پر ہمارے بھائی اسلام لائے ہیں اس پر ہم بھی اسلام لاتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا:
غفار غفراللّٰہ لھا و اسلم سا لمھا اللّٰہ (۴۶)
’’اللہ تعالیٰ غفار کی مغفرت کرے اور اسلم کو سلامت رکھے‘‘
حوالہ جات
(۱) اسد الغابہ ، تذکرہ عبداللہ بن عثمان ابو بکر الصدیقؓ، ۳ / ۲۰۶
(۲) اسد الغابہ ، تذکرہ عثما نؓ بن عفان ، ۳/ ۳۷۶۔ ابنِ حجر،ابوالحسن احمد بن علی ،’’الاصابہ فی تمییز الصحابۃ‘‘، تذکرہ عبداللہ بن عثمان ابو بکر الصدیقؓ ، ۲/۳۴۲،دارا احیائالتراث العربی ،بیروت،۱۳۲۸ھ
(۳) ابن ہشام ، اسلام ابی بکر الصدیقؓ ، ۱/ ۲۸۶، ۲۸۷
(۴) ابن ہشام ، ذکر من اسلم من الصحابۃ بدعوۃ ابی بکرؓ ،۱/ ۲۸۷۔۲۹۷
(۵) ا سد الغابہ ، تذکرہ ام شریکؓ الدوسیہ ، ۵/ ۵۹۴
(۶) ایضاً،تذکرہ فاطمہ بنت الخطابؓ ، ۵/ ۵۱۹
(۷) الموطا، کتاب النکاح ،باب نکاح المشرک اذااسلمت زوجتہ قبلہ ، ح:۶۲۰، ص:۳۴۲
(۸) الاصابہ ،تذکرہ ام سلیمؓ بنت ملحان ، ۴/ ۴۶۱ ۔اسد الغابہ، تذکرہ زیدؓ بن سہل ، ۲/ ۲۳۲
(۹) ابن ھشام ، ۲/۷۱۴
(۱۰) البدایۃ ،۳/۲۹،۳۰۔الاصابہ ، تذکرہ ام الخیرؓبنت صخر ،۴/ ۴۴۷۔اسدالغابہ ، تذکر ہ ام الخیرؓ بنت صخر، ۵/۵۸۰
(۱۱) ابن ہشام ، اول من جھر بالقرآن ، ۱/ ا۳۵، ۳۵۲۔اسد الغابہ ، تذکرہ عبداللہؓ بن مسعود ، ۳ /۲۵۶، ۲۵۷
(۱۲) صحیح البخاری ، کتاب المناقب ، باب قصہ اسلام ابی ذرؓ الغفاری ، ح : ۳۵۲۲، ص :۵۹۲۔ ایضاً کتاب مناقب الانصار ، باب اسلام ابی ذرؓ الغفاری ، ح :۳۸۶۱ ، ص :۶۴۸
(۱۳) اسد الغابہ، تذکرہ عثمانؓ بن مظعون ، ۳/۳۸۶
(۱۴) صحیح البخاری ، کتاب التیمم، باب الصعید الطیب وضوء المسلم ،ح :۳۴۴، ص:۵۹
(۱۵) ابن ہشام ، ذکر الہجرۃ الاولیٰ الی ارض الحبشہ ، ۱/ ۳۵۸
(۱۶) زادالمعاد ،۳/ ۲۳
(۱۷) سیرۃ النبی ﷺ ، ۱/۱۴۹، ۱۵۰
(۱۸) زاد المعاد ، ۳/۲۳
(۱۹) صحیح البخاری ، کتاب مناقب الانصار ، باب ہجرۃ الحبشہ ، ح:۳۸۷۶، ص:۶۵۱۔ المستدرک ، مناقب ابی موسٰیؓالاشعری ، ۳/۴۶۴۔اسدالغابہ ، تذکرہ ابو موسٰیؓ الاشعری ، ۵/ ۳۰۸
(۲۰) ابنِ قیم الجوزیۃ ، ابوعبداللہ محمد بن یزید،’’زاد المعاد ‘‘، ۳/۲۶،موسس الرسالۃ ،بیروت ،۱۹۷۹ء
(۲۱) ابن ہشام ارسال قریش الی حبشۃفی طلب المہاجرین الیھا، ۱/ ۳۷۳۔ المسند، حدیث جعفرؓ بن ابی طالب ،
ح ۱۷۴۲،۱/ ۳۳۳
(۲۲) ابن ہشام ، ارسال الی الحبشہ فی طلب المہاجرین الیہا، ۱/ ۳۷۳،۔المسند، حدیث جعفرؓ بن ابی طالب ، ح :۱۷۴۲، ۱/ ۳۳۲۔۳۳۴
(۲۳) ابنِ ہشام،ارسال قریش الی الحبشۃ فی طلب المہاجرین الیھا،۱/۳۷۳۔ المسند ،حدیث جعفرؓ بن ابی طالب،
ح: ۱۷۴۲، ۱/۳۳۴
(۲۴) یہ تمام واقعات ،سیرت ابنِ ہشام اور مسندِ احمد میں موجود ہیں۔امام احمد بن حنبل اور ابنِ ہشام کا سلسلہ سند بھی ایک ہے۔محمد بن اسحاق ،زہری،ابوبکر بن عبدالرحمنؓ بن الحرث بن ہشام مخزومی،ام سلمہؓ ۔یہ سب ثقہ راوی ہیں اور سب سے آخری راوی ام المومنین حضرت ام سلمہؓ ہیں جو خود اس واقعہ میں شریک تھیں اور اس وقت تک رسول اللہ ﷺ کی زوجیت میں نہیں آئیں تھیں بلکہ اپنے پہلے شوہر ابوسلمہؓ بن عبدالاسد کے ساتھ حبشہ ہجرت کرکے گئی تھیں۔(ابنِ ہشام ،ارسال قریش الی الحبشہ فی طلب المہاجرین ،۱/۳۷۳۔۳۷۵۔ المسند،حدیث جعفرؓ بن ابی طالب،ح:۱۷۴۲، ۱/۳۳۲۔۳۳۴)
(۲۵) ابنِ ہشام،۱/۴۱۸
(۲۶) خطباتِ بہاولپور،ص:۴۰۳
(۲۷) ابنِ ہشام،خروج الحبشہ علی النجاشی ،۱/۳۷۹۔ اسدالغابہ،تذکرہ اصحمہؓ ،۱/۱۴۲۔ صحیح البخاری،کتاب مناقب الانصار،بابموت النجاشی،ح:۳۴۷۷،ص:۶۵۱
(۲۸) محمد حمید اللہ ،ڈاکٹر،’’الوثائق السیاسیۃفی العھد النبوی والخلافۃ الراشدۃ‘‘،ص:۴۹،قاہرہ ،۱۹۴۱ء
(۲۹) ابن ہشام،اسلام عمروؓ بن العاص وخالدؓ بن الولید،۳/۳۰۴۔اسد الغابہ،تذکرہ عمروؓ بن العاص،۴/۱۱۶
(۳۰) ابن ہشام،اسلام عمروؓ بن العاص وخالد بن الولید،۳/۳۰۴۔اسد الغابہ،تذکرہ عمروؓ بن العاص ،۴/۱۱۶
(۳۱) اسد الغابہ،تذکرہ ذومخبرؓ، ۲/۱۴۴
(۳۲) اسد الغابہ،تذکرہ ابرہہؓ ۱/۴۴
(۳۳) یہ تمام نام اور ان کے حالات زندگی اسد الغابہ اور الاصابہ میں ان صحابہ کے تذکروں میں موجود ہیں۔
(۳۴) المسند ،مسند عبداللہؓ بن مسعود ،ح:۳۵۸۷،۱/۶۲۶
(۳۵) ابنِ کثیر،’’البدایۃ‘‘ ۳/۱۴۲۔ ایضاً،’’ السیرۃ النبویۃ‘‘،۲/۱۶۹۔ الہندی،علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین ’’کنز العمال ‘‘ فضائل ابی بکر الصدیقؓ،۶/۳۱۹،موسسۃ الرسالہ،بیروت
(۳۶) ابن کثیر، ابوالفداء،اسماعیل ابنِ عمر’’السیرۃ النبویۃ‘‘،۲/۱۷۱،دارالمعارفۃ،بیروت،۱۹۷۶ء
(۳۷) ابنِ کثیر’’ البدایۃ ‘‘،۳/۱۴۴
(۳۸) اسدالغابہ،عبداللہؓ بن قیس ابو موسیٰ اشعریؓ، ۳/۲۴۵
(۳۹) صحیح البخاری،کتاب مناقب الانصار،باب ہجرۃ الحبشۃ،ح:۳۸۷۶، ص:۶۵۱۔ المستدرک،مناقب ابی موسیٰ الاشعریؓ۳/۴۶۴۔ اسدالغابہ،تذکرہ ابوموسیٰ الاشعریؓ،۵/۳۰۸
(۴۰) اسد الغابہ،تذکرہ ضمادؓ بن ثعلبۃ الازدی،۳/۴۱،۴۲ ۔ الاصابہ،تذکرہ ضمادؓ بن ثعلبۃ الازدی،۲/۲۱۰
(۴۱) اسد الغابہ،تذکرہ ضمادؓ بن ثعلبۃ الازدی،۳/۴۱۔۲۴
(۴۲) المسند،مسندجابرؓ بن عبداللہ ،ح:۱۴۶۵۴، ۴/۳۴۹
(۴۳) ابنِ ہشام،قصۃ اسلام الطفیلؓ بن عمرو دوسی۱/۴۳۲۔ اسدالغابہ،تذکرہ طفیلؓ بن عمروالدوسی،۳/۵۴
(۴۴) ابن سعد ,وفدِ دوس،۱/۳۵۳
(۴۵) صحیح مسلم،کتاب فضائل ا لصحابۃ،باب من فضائل ابی ذرؓ،ح:۶۳۵۹،ص،۱۰۸۶،۱۰۸۸
(۴۶) ایضاً
حواشی
- ان کا مشہور نام ’’النحام ‘‘ ہے او راس نام سے اس کی وجہ شہرت رسول اللہﷺکا یہ فرمان ہے: لقد سمعت نحمہ فی الجنتہ ’’میں نے جنت میں ان کے کنگھارنے کی آواز سنی ‘‘ (ابن ھشام ذکر من اسلم من الصحابہ بدعوۃ ابی بکرؓ ، ۱/ ۹۲۵)
- لبیدؓ بن ربیعہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ۔قبول اسلام کے بعد انہوں نے شعر کہنا ترک کر دیا ۔ایک روز حضرت عمرفاروق ؓ نے لبیدؓ بن ربیعہ سے کہا : مجھے اپنے اشعار سناؤ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی شعر نہ کہوں گا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تعلیم کر دی ہے ۔حضرت لبیدؓ بن ربیعہ نے ایک سو چالیس سال کی عمر میں امیر معاویہؓ کے دور حکومت میں انتقال فرمایا ۔(اسدالغابہ ،تذکرہ لبیدؓبن ربیعہ ، ۴/ ۲۶۲)
- حبش عرب کے جنوب میں واقع ہے حبش عربی نام ہے ۔یونانی میں اسے ایتھوپیا (Ethiopia)کہتے ہیں۔دنیا کے موجودہ نقشے میں یہ اے۔بی سینا کے نام سے موسوم ہے۔حبشی زبان میں بادشاہ کو نجوس (negus)کہتے ہیں۔نجاشی اسی لفظِ نجوس سے معرب ہے۔(سیرۃ النبیﷺ،۱/۱۵۵) بعثت نبویﷺکے زمانے میں حبشہ کے تخت پر اصحمہ نامی بادشاہ متمکن تھا۔نجاشی نے حضرت جعفرؓکے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔جب نجاشی کی وفات ہوئی تو آپﷺنے نجاشی کی غائبانہ نمازِ جنازہ ادا فرمائی۔ (صحیح البخاری ، کتاب مناقب الانصار ، باب موت النجاشی ، ح: ۳۸۷۷، ص:۶۵۱) نجاشی کا خاندان چوتھی صدی عیسوی سے حبش پر حکمران تھا۔یہ خاندان پہلے بت پرست تھا رومی شہنشاہیت نے مصر کے ذریعہ یہاں عیسائیت کی بنیاد رکھی۔ اسکندریہ کے ایک بشپ نے یہاں اپنے مشن کا ایک مرکز قائم کیا اور پھر رفتہ رفتہ پورے ملک میں عیسائیت پھیل گئی۔ ( ڈبلیو ، پی ، ہیرس ، پادری ، ’’تواریخ مسحیے کلیسا ‘‘کرسچین نالج سوسائٹی ، لاہور ، ص:۲۶۸، ۱۹۲۵ء)
- حضرت عیسیٰ کے متعلق نجاشی نے اسلامی نقطۂ نظر کو جو پزیرائی بخشی ڈاکٹر حمید اللہ نے ا س کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے:
’’نجاشی فرقۂ طبیعت واحد کا(یعنی مانو فرائٹ)عیسائی تھا۔اور ان دنوں اس فرقے اور یونان کے عیسائیوں میں بڑے سخت اختلافات تھے،آخر الذکر اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ ؑ میں بوقت واحد دو طبیعتیں تھیں، انسانی اور خدائی بھی۔ابرہہ جو (یمن میں)نجاشی کا نائب تھا۔حضرت عیسیٰ ؑ کو ابن اللہ نہیں مانتا تھابلکہ صرف مسیح اللہ۔غالباً نجاشی کے بھی یہی عقائد ہوں گے۔ اور یہ مسلمانوں کے عقائد کے بہت مماثل ہیں‘‘۔ (محمد حمید اللہ،ڈاکٹر،’’رسول اکرم ؐ کی سیاسی زندگی‘‘دارالاشاعت کراچی،۱۹۸۷ء ،ص۱۲۷)
(جاری)
تصحیح وتوضیح: دکتر غلام حسین یوسفی
شرکت سہامی انتشارات خوارزمی
چاپ سوم: مہر ماہ ۱۳۷۳ھ ش ۔ تہران
اردو داں طبقہ کے لیے شیخ سعدی کی ’گلستاں‘ محتاج تعارف نہیں ۔ شیخ سعدی (م ۶۹۰ھ)نے یہ کتاب ۶۵۶ھ میں تصنیف کی اور خود ان کی حیات ہی میں اس کا شہرہ ہر طرف پھیل گیا۔ یہ کتاب خواص وعوام میں یکساں مقبول رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں کہ ’بوستان‘ کی طرح شیخ کی ’گلستاں‘ مختلف مسلم ممالک بشمول ہندوستان کے نصاب درس میں اب تک داخل ہے۔ اس کتاب پر کثرت سے شرحیں لکھی گئیں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔
ایران وہندوستان میں گلستاں کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے جو مختلف خصوصیات کے حامل ہیں۔ پیش نظر ایڈیشن تحقیق، تصحیح اور توضیح کے جدید اصولوں کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین یوسفی تمام محبان سعدی کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پوری جان کاہی سے عالمی ادب کے اس شہ پارہ کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ سطور ذیل میں اس جدید ایڈیشن کا ایک تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔
باریک خط سے متوسط سائز کے آٹھ سو پندرہ صفحوں پر پھیلا ہوا یہ محقق نسخہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: متن کتاب، توضیحات مربوط بہ متن گلستاں، اور شرح نسخہ بدلہا، جس میں متن گلستان ص ۴۹ سے ۱۹۱ تک ہے۔
متن گلستاں سے پہلے ’’استاد سخن‘‘ کے عنوان سے ایک مفصل بحث ہے جو گلستاں کے ایک تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ پر مشتمل ہے۔ یہ بحث بہت ہی کارآمد ہے۔ اس میں گلستاں کے امتیازات نمایاں کرنے کے علاوہ گلستاں کے مطالعہ کے وقت ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ’’استاد سخن‘‘ میں محقق نے پہلے گلستاں کی اس نمایاں ترین خصوصیت پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ زندگی کے بیش بہا تجربات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے گہرے اور عمیق مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ایک مرد جہاں دیدہ، پختہ کار اور سوجھ بوجھ کا حامل ہے، جو زندگی کے بے شمار نشیب وفراز سے گزرا ہے، جس نے شہر شعر وعشق شیراز اور اس زمانے کے متمدن شہروں کا قریب سے مطالعہ کیا ہے، جسے علماء ومشائخ اور ملوک وامرا سے لے کر عوام الناس تک کے ہر طبقہ سے قریبی اور طویل صحبت واختلاط کے مواقع حاصل رہے ہیں۔ اس دنیا میں اور لوگوں کو بھی یہی خصوصیات حاصل رہی ہیں لیکن شیخ سعدی جیسی چشم بینا، ذہن روشن، نگاہ باریک بیں، اہلیت مردم شناسی اور قوت ادراک واستفادہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوا ہے۔ فاضل محقق نے گلستاں کی اس خصوصیت کو مزید واضح کرنے کے لیے اندرون کتاب سے بعض مثالیں پیش کی ہیں اور قدرے تفصیل سے اس خصوصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔
گلستاں کی خصوصیات اور امتیازات پر ایک طویل گفتگو کے بعد محقق نے گلستاں پر کیے جانے والے بعض اعتراضات کا جائزہ لیا ہے۔ ایک عام اعتراض یہ ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں شیخ کے پیش نظر کوئی مرکزی فکر (System) نہیں جو گلستاں کے مختلف ابواب کے لیے جامع عنوان کی حیثیت رکھتی ہو، بلکہ یہ کتاب ایک کشکول کی طرح معلوم ہوتی ہے جس میں شیخ نے اپنی سیاحت کے تیس سالہ متفرق ومتنوع تجربات قلم بند کیے ہیں۔ ڈاکٹر یوسفی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اجتماعی اور سیاسی اخلاقیات کے سلسلے میں شیخ نے بوستاں میں منظم اصول پیش کیے ہیں اور گلستاں میں آقای دکتر زریں کوب کے الفاظ میں انسان اور انسانی دنیا کی تصویر کشی ان تمام محاسن ومعایب اور مطابقات وتناقضات کے ساتھ کی گئی ہے جو خود انسان اور انسانی دنیا میں موجود ہیں۔ اس میں انسانی زندگی کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جس طرح یہ بذات خود ہے نہ کہ جس طرح اسے ہونا چاہیے اور خود دنیا، انسان کی طرح تناقض وشگفتگی کے مختلف مظاہر سے خالی نہیں۔
لوگوں نے عام طور سے گلستاں کی ان حکایتوں کو شک وشبہ کی نگاہ سے دیکھا ہے جن میں شیخ سعدی خود جزو داستان کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ فاضل محقق کے خیال میں ان تمام داستانوں میں شیخ کی موجودگی واقعہ کے مطابق نہیں ہے اور بڑی حد تک اس میں افسانہ کا رنگ شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان قصوں کو اس بات کی دلیل میں نہیں پیش کیا جا سکتا کہ ان تمام واقعات میں شیخ سعدی کی اسی طرح شرکت رہی ہے جس طرح انہوں نے بیان کی ہے اور نہ گلستاں کی حکایات یہ ثبوت فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں کہ شیخ نے ان جگہوں کا سفر بھی کیا ہے جہاں وہ کہانی کا کوئی نہ کوئی کردار پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیخ نے یہ طرز اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس سے قصص وحکایات کی اثر اندازی بڑھ جاتی ہے۔ فاضل محقق کے اس موقف سے علامہ شبلی نعمانی کے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے کہ ’بوستاں‘ میں شیخ کے سفرہندوستان کا قصہ محض رنگ آمیزی داستاں ہے۔
اس کے بعد ڈاکٹر یوسفی لکھتے ہیں کہ شیخ سعدی کی مقبولیت اور فارسی زبان میں ان کے اثرات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے چار سو سے زیادہ اشعار اور جملے فارسی زبان میں مثل کا مقام پیدا کیے ہوئے ہیں اور عام اجتماعی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں اور سعدی کی گلستاں اب تک اسی طرح مقبول ہے۔ نثر فارسی پر سعدی کا ایک عظیم احسان یہ ہے کہ انہوں نے اسے تکلف وتصنع کے چنگل سے نجات دے کر فطری طرز اور معتدل اسلوب عطا کیا۔ مصحح نے کتنی سچی بات کہی ہے کہ اگر گلستاں میں سے عمدہ قطعات منتخب کر کے بطور مثال پیش کیے جائیں تو شاید کتاب کا اکثر حصہ نقل کرنا پڑے۔ گلستاں میں قرآنی آیات، احادیث اور عربی اشعار وامثال اس طرح برمحل اور سیاق کلام کے ساتھ مربوط ہیں کہ ان سے کوئی ثقالت نہیں پیدا ہوتی بلکہ اس سے سخن کی اثر انگیزی اور سلاست میں اور اضافہ ہو گیا ہے اور زبان مزید شیریں وپر معنی ہو گئی ہے۔
فاضل محقق نے گلستاں کی معجزانہ سہل نگاری، ماہرانہ منظر کشی اور دقیق تصویر کشی کی خصوصیات پر جدا جدا مفصل گفتگو کی ہے۔
اس قیمتی بحث وگفتگو کے بعد گلستاں کا پورا متن ہے جو ضروری باریک بینی، مکمل تصحیح اور سترہ مخطوطہ نسخوں اور معتبر مطبوعہ نسخوں، شرحوں اور ترجموں سے استفادہ کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ نسخوں کے اختلافات آخر کتاب میں صفحہ اور سطر کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ موجودہ متن لارڈ گرینوی کے مخطوطہ نسخہ پر مبنی ہے۔ یہ نسخہ عبد الصمد بن محمد بن محمد بن خلیفہ بن عبد السلام بیضاوی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور کتابت کی تاریخ ماہ صفر ۷۲۰ھ ہے۔ متن میں قوسین کے درمیان دوسرے نسخوں کے ان ضروری اضافوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن سے جملوں کی وضاحت یا کوئی مزید فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔
پورا متن بہت واضح ہے۔ ہر حکایت الگ الگ ہے۔ اشعار نمایاں طریقہ سے لکھے گئے ہیں۔ یہ متن ہندوستانی نسخوں کی طرح بین السطور حواشی اور تشریحی نوٹ سے پاک ہے۔ فاضل محقق نے متن کے بعد توضیحات کے عنوان سے شرح پیش کی ہے اور اس کے بعد نسخوں کے اختلافات دکھائے ہیں۔ متن کے اندر نہ کوئی تشریحی نوٹ ہے اور نہ کوئی توضیحی کلمہ۔ عربی عبارتوں پر پوری حرکات دی ہیں اور ساتھ ہی مختلف فارسی الفاظ کے تلفظ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
مکمل متن کے بعد توضیحات ہیں جن میں عربی عبارتوں کی تشریح کے ساتھ بہت سے فارسی کلمات اور تعبیرات کی مکمل تحقیق پیش کی گئی ہے۔ اشخاص اور مقامات کی تشریح کے علاوہ جگہ جگہ قیمتی اور مفصل بحثیں ہیں۔ متقدمین کے اشعار اور جملے بطور تائید پیش کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں شیخ سعدی کے مآخذ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان توضیحات میں سراج الدین علی خان آرزو کی خیابان گلستاں، دہلی ۱۲۶۷ھ اور محمد حسین برہان تبریزی کی ’’برہان قاطع‘‘ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی ’’برہان قاطع‘‘ ہے جس پر مرزا غالب سخت ناراض تھے اور جس کی تردید میں ’’قاطع برہان‘‘ تحریر کی گئی اور پھر سرزمین ہند میں اچھی خاصی معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ ذیل میں توضیحات کے بعض نمونے دیے جا رہے ہیں:
’’ذکر جمیل سعدی کہ در افواہ عام افتادہ است وصیت سخنش کہ در بسیط (زمین) منتشر گشتہ وقصب الجیب حدیثش کہ ہمچوں شکر می خورند‘‘ (ص ۱۵)میں ’’قصب الجیب‘‘ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کلمہ کے ضبط اور مفہوم میں طویل بحثیں کی گئی ہیں۔ پھر تفصیل سے ان بحثوں کو نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس موضوع پر دو فاضل ایرانیوں نے ’’قصب الجیب‘‘ کے عنوان سے مستقل مضامین بھی لکھے ہیں جن کا حوالہ فاضل محقق نے یہاں دیا ہے۔
’’حکمت محض است اگر لطف جہاں آفریں خاص کند بندہ ای مصلحت عام را‘‘ (ص ۵۵) میں لفظ ’’اگر‘‘ کے مفہوم پر طویل گفتگو کی ہے۔ بعض لوگوں نے گلستاں اور بوستاں میں اس طرح سے ’’اگر‘‘ کے استعمال پر مستقل بحثیں لکھی ہیں۔ ان بحثوں میں ایک رائے یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر ’’اگر‘‘ ایجاب وتاکید کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔
’’خورشید در سیاہی شد یونس اندر دہان ماہی شد‘‘ (ص ۶۱) میں دوسرے مصرعہ کی تشریح میں شارحین کے اختلاف پر روشنی ڈالی ہے۔ اس موضوع پر بھی ایک صاحب نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔
’’با بداں یار گشت ہمسر لوط خاندان نبوتش گم شد‘‘ (ص ۶۲) ہندوستانی نسخوں میں پہلا مصرعہ اس طرح ہے: ’’پسر نوح با بداں بنشست‘‘ دونوں نسخوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ فاضل محقق نے پہلی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا ہے: ’’اما علاوہ برآں کہ متن چاپ حاضر مطابق ضبط نسخہ ہائی معتبر ست، مضمون مصراع دوم با سرگزشت ہمسر لوط بیشتر تناسب دارد‘‘ یہ بات واضح نہیں ہے کہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے مصرعہ کا مفہوم لوط علیہ السلام کے اہل خانہ کی سرگزشت سے زیادہ مطابق ہے۔
’’سرہنگ زادہ ای بر در سرای اغلیمش دیدم کہ عقل وکیاستے‘‘ (ص ۶۳) میں اغلیمش کی تعیین کی کوشش کی ہے جس کا عہد سعدی کے ہوش سنبھالنے سے پہلے کا ہے۔ اس پر اعتراض پیدا کر کے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ سعدی نے اغلیمش کی زندگی ہی میں اس قصر کی زیارت کی ہو۔
گلستاں کے اندر بعض تاریخی گرفتیں کی گئی ہیں۔ میرے خیال میں گلستاں جیسی کتابوں پر مورخانہ نگاہ ڈالنا بد ذوقی ہے۔ ذیل میں ایک مثال دی جا رہی ہے جس میں ناقدین نے سعدی کی تاریخی فرو گزاشت پر گفتگو کی ہے:
’’ہارون الرشید را چوں ملک مصر مسلم شد گفت: بخلاف آں طاغی کہ بہ غرور ملک مصر دعوی خدائی کرد نبخشم ایں ملک را مگر بہ خسیس ترین کسے از بندگان سیاہے داشت خصیب نام، ملک مصر بہ وی ارزانی داشت‘‘ (ص ۸۴) ابن بطوطہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ خصیب ایک سیاہ غلام تھا لیکن مورخین کے نزدیک خصیب ایرانی نژاد ہے نہ کہ حبشی۔ فاضل محقق نے شیخ سعدی اور ابن بطوطہ دونوں کی غلطی کی نشان دہی کی ہے۔
’’چندانکہ مرا شیخ اجل ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہ ترک سماع فرمودے‘‘ (ص ۹۴) گلستاں کے تمام شارحین نے اس پر بحث کی ہے کہ ابن جوزی سے کون ابن جوزی مراد ہیں۔ عام رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد ابن جزی دوم متوفی ۶۵۶ھ ہیں نہ کہ امام ابن جوزی جن کا سال وفات ۵۹۷ھ ہے۔ فاضل محقق نے آقای محمد محیط طباطبائی کے حوالہ سے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ اس سے مراد شیرازی الاصل شیخ الناصح ابو الفرج عبد الرحمن بن نجم الدین عبد الوہاب بن شیخ ابو الفرج الجوزی ہیں۔
یہاں اس بات کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ توضیحات مذہبی تعصب سے پاک ہیں۔ اس میں ضرورت کے موقعوں پر ائمہ اسلام کی رایوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ مثلاً ’’الفقر فخری‘‘ (ص ۱۶۳) کی تشریح میں لکھتے ہیں: ’’در سفینۃ البحار، طبع نجف، ۲/۳۷۸، جزء حدیث نبوی ذکر شدہ، ومولف اللولو المرصوع (ص ۵۵) بہ نقل از ابن تیمیہ آں را از احادیث موضوع شمردہ است‘‘ (ص ۴۹۷، ۴۹۸)
صحابہ کرامؓ کی حرمت بھی ملحوظ ہے مثلاً ذو الفقار علی (ص ۵۳) کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے: ’’علی بن ابی طالب (ع) امام اول شیعیان وخلیفہ چہارم از خلفاے راشدین کہ دورہ خلافتش از ۳۵ تا ۴۰ بودہ است‘‘۔ یہاں فاضل محقق نے خلفائے ثلاثہ کے لیے راشدین کا لفظ استعمال کیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ ص کے بارے میں لکھا ہے: ’’کنیہ یکے از اصحاب پیغمبر (ص) کہ بہ سال ۵۷، ۵۸ یا ۵۹ھ در گزشت ..... ابو ہریرہ ہمیشہ در خدمت پیغمبر بود، ونیز چوں حافظہ ای قوی داشت حدیث ہاے بسیار ازو روایت کردہ اند‘‘ (ص ۳۵۵)
اس کے بعد نسخوں کے اختلافات ’’شرح نسخہ بدلہا‘‘ کے عنوان سے پیش کیے ہیں۔ محقق نے گلستاں کی تصحیح میں سترہ مخطوطہ نسخوں سے استفادہ کیا ہے۔ مقدمہ میں ہر نسخہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ مطبوعہ نسخوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ان مطبوعہ نسخوں میں سے ایک کلکتہ سے شائع شدہ سنہ ۱۸۲۵ء کا نسخہ ہے جو مطبوعہ نسخوں میں سب سے قدیم ہے۔ جس نسخہ پر متن میں اعتماد کیا گیا ہے، وہ ہمارے یہاں ہندوستان کے مطبوعہ نسخوں سے قدرے مختلف ہے۔ فاضل محقق نے نسخوں کے سارے اختلافات مفصل بیان کیے ہیں۔ ذیل میں بعض ایسی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جہاں ہندوستانی نسخوں سے اختلاف ہے:
’’گلے خوشبوی در حمام روزے ۔رسید از دوست مخدومی بدستم‘‘(ص ۵۱)
ہندوستانی اور بعض دوسرے نسخوں میں ’’مخدومی‘‘ کے بجائے ’’محبوبے‘‘ ہے۔
’’کمال ہمشیں در من اثر کرد‘‘ (ص ۵۱)
ہندوستانی نسخوں میں ’’جمال ہمنشیں‘‘ ہے۔
’’سرچشمہ شاید گرفتن بہ بیل‘‘ (ص ۶۱)
ہمارے یہاں کے نسخوں میں بیل کے بجائے ’’میل‘‘ ہے۔
اس کے بعد لغات وتراکیب کی فہرست ہے جس میں حروف تہجی کے لحاظ سے ان سارے الفاظ وتراکیب کو جمع کیا ہے جن کی تشریح توضیحات میں پیش کی ہے۔
آخر میں قرآن کریم کی آیات، احادیث شریفہ، عربی اشعار اور جملوں کے آغاز، آغاز اشعار فارسی، امثال وحکم، اعلام اور مراجع کے الگ الگ انڈکس دیے گئے ہیں۔
آخر میں اپنے اس تاثر کا اعادہ کرتا ہوں کہ یہ گلستاں کا جدید ترین اور مکمل ترین ایڈیشن ہے اور مطالعہ سعدی کے میدان میں ایک بیش بہا اضافہ۔