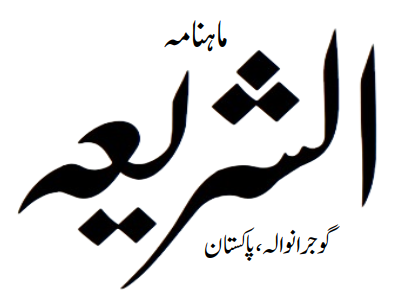افغانستان میں عالم اسلام کی آرزوؤں کا خون
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
افغانستان میں روسی استعمار کے تسلط کے خلاف غیور افغانوں نے جہاد کے مقدس عنوان پر علم بغاوت بلند کیا تو دنیائے اسلام کے دینی حلقوں میں جوش و جذبہ کی ایک لہر دوڑ گئی کہ جہاد کا بابرکت عمل جو ایک عرصہ سے مغربی استعمار کی سازشوں کے باعث ملت اسلامیہ کی عملی زندگی سے نکل چکا تھا ایک بار پھر نظریاتی بنیادوں پر سفرِ نو کا آغاز کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد افغانستان کے دوران نہ صرف پورے عالم اسلام کے دل افغان مجاہدین کے ساتھ دھڑکے بلکہ دنیا کے ہر خطہ سے پرجوش مسلم نوجوانوں نے افغانستان کی سرزمین پر پہنچ کر اس جہاد میں عملاً حصہ لیا اور اس طرح جہاد افغانستان عالم اسلام کی نظریاتی یکجہتی اور دینی تحریکات میں وحدت و اشتراک کے عنوان کے طور پر دنیا بھر کی توجہات کا مرکز بن گیا۔
جہاد افغانستان کی کامیابی اور کابل میں مجاہدین کی مشترک حکومت کے قیام کے بعد دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کو یہ امید تھی کہ اب افغانستان میں ایک نظریاتی اسلامی حکومت قائم ہوگی اور مجاہدین کی جماعتیں اور قائدین مل جل کر افغانستان کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ اسلام کے عادلانہ نظام کا ایک مثالی عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے جو دیگر مسلم ممالک میں نفاذ اسلام کی تحریکات کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ، بعض افغان راہنماؤں کی ناعاقبت اندیشی اور ہوسِ اقتدار نے عالم اسلام کی آرزوؤں کا سربازار خون کر دیا ہے اور کابل کی خوفناک خانہ جنگی نے دنیا بھر کی دینی تحریکات کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔
یہ درست ہے کہ اس خانہ جنگی کے پس منظر میں بیرونی لابیاں کام کر رہی ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا کا واحد ٹھیکیدار امریکہ افغانستان کے مختلف گروپوں کے پاس موجود اسلحہ کی بھاری مقدار کو کابل کی مشترکہ کمان کی تحویل میں نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ اس کے خیال میں اس صورت میں کابل اس قدر طاقتور ہو جائے گا کہ اردگرد کی دیگر ریاستوں پر اثر انداز ہو سکے گا۔ اس لیے امریکہ اس اسلحہ کو خانہ جنگی میں اسی طرح ضائع کرا دینا چاہتا ہے جس طرح اس نے ایران میں اپنا چھوڑا ہوا اسلحہ عراق ایران جنگ کی صورت میں ضائع کرا دیا تھا۔
اسی طرح امریکہ افغانستان میں ایک نظریاتی اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے عملی نفاذ کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظاموں کی ناکامی کے بعد عالم اسلام اور اسلام کے عادلانہ اور متوازن فلاحی معاشرہ کا آغاز ہوگا جسے آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چند ماہ قبل جنرل رشید دوستم کے دورۂ امریکہ کے موقع پر حکمت عملی یہ طے کر لی گئی تھی کہ یا تو جنرل دوستم کے اشتراک کے ساتھ کابل میں ایک ڈھیلی ڈھالی حکومت بنوا دی جائے اور یا پھر افغانستان کو تقسیم کر کے وسطی ایشیا کی نو آزاد مسلم ریاستوں اور افغانستان کے درمیان ایک نئی بفر اسٹیٹ قائم کر دی جائے تاکہ کابل کی حکومت ان ریاستوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ ساری باتیں تسلیم، مگر سوال یہ ہے کہ اس سب کچھ کے لیے آلۂ کار کون ہے اور امریکہ ان مقاصد کے لیے استعمال کسے کر رہا ہے؟ پروفیسر برہان الدین ربانی، انجینئر حکمت یار اور انجینئر احمد شاہ مسعود اگر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اس سوال کا جواب تلاش کر سکیں تو یہ ان کا پوری امت پر احسان ہوگا۔
اس ساری صورتحال اگر کوئی بات کسی حد تک اطمینان بخش ہے تو وہ یہ ہے کہ اس افسوسناک خانہ جنگی میں علماء کی جماعتیں براہ راست شریک نہیں ہیں اور افغان مسلمانوں کا بے مقصد اور بے گناہ خون بہانے کے اس شرمناک عمل میں مولانا محمد نبی محمدی، مولانا محمد یونس خالص، مولانا جلال الدین حقانی، اور مولانا ارسلان رحمانی کا نام سامنے نہیں آرہا۔ گویا اس کشمکش میں دینی مدارس کی تربیت یافتہ قیادت کا کردار نسبتاً متوازن اور معتدل ہے۔ لیکن ان چاروں بزرگوں کی خدمت میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ افغان مجاہدین کی خانہ جنگی میں ان کا فریق کے طور پر سامنے نہ آنا ایک اچھا عمل ہے جس پر وہ بلاشبہ تحسین کے مستحق ہیں لیکن یہ کردار کافی نہیں ہے۔ انہیں خانہ جنگی کو رکوانے کے لیے مصالحت کنندہ کا کردار ادا کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ان لوگوں کو ان کے منفی طرز عمل کے سنگین نتائج کا احساس دلانا چاہیے جو محض شخصی انا یا گروہی ترجیحات کی خاطر شعوری یا غیر شعوری طور پر عالمی استعمار کا آلۂ کار بن کر افغانستان کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں۔
اقبالؒ کا تصورِ اجتہاد
ڈاکٹر محمد آصف اعوان
(۹ نومبر ۱۹۹۳ء کو گوجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کے ہال میں علامہ اقبالؒ کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریب میں یہ مقالہ پڑھا گیا۔)
علامہ محمد اقبالؒ کو بلاشبہ بیسویں صدی کا ایک عظیم مفکر اور اسلام کا ممتاز ترین ترجمان کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب و ثقافت اور اصول و قوانین کے مطالعہ میں گزارا، جس سے انہیں اسلام کی اصل روح کو سمجھنے اور جاننے کے لیے گہری بصیرت حاصل ہوئی۔ اقبال اسلام کی حقانیت اور ابدیت پر کامل یقین اور پختہ ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ اسلامی اصول و قوانین کی نئی تشریح و تعبیر کی بھی سخت ضرورت ہے تاکہ اسلام جدید دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے اور دنیا پر یہ حقیقت واضح ہو کہ اسلام کسی ایک عہد اور زمانے کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ اس کے اصول و قوانین میں اتنی لچک اور پھیلاؤ ہے کہ یہ ہر دور کا ساتھ دے سکے اور ہر مسئلے کا حل پیش کر سکے۔
اقبال حرکت و حرارت کا پیامبر ہے، جمود اس کے نزدیک شر اور حرکت سب سے بڑی خیر ہے۔ بقول خلیفہ عبد الحکیم ’’اقبال کے لیے ہر وہ تحریک خوش آئند تھی جو زندگی کے جمود کو توڑ دے‘‘1 چنانچہ اقبال نے اپنے دور میں ترکی اور ایران میں اٹھنے والی نئی سیاسی اور معاشرتی تحریکوں کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی تعریف کی۔ اقبال کا خیال یہ ہے کہ
’’تہذیب و ثقافت کی نظر سے دیکھا جائے تو بحیثیت ایک تحریک، اسلام نے دنیائے قدیم کا یہ نظریہ تسلیم نہیں کیا کہ کائنات ایک ساکن و جامد وجود ہے، برعکس اس کے وہ اسے متحرک قرار دیتا ہے۔‘‘2
اقبال چاہتے تھے کہ اسلام کے اصول و قوانین کا ازسرنو جائزہ لے کر زمانۂ حال کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ کیونکہ اسی طریقے سے اسلامی اصول و قوانین کی ابدیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ اگر موجودہ دور کے تقاضوں کا احساس نہ کیا گیا اور اسلامی اصول و قوانین کی تدوینِ نو کر کے موجودہ مسائل کا حل پیش نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے سے ایمان اٹھ جائے، اور وہ جدید مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اسلام کی رائے سنے یا اس کا انتظار کیے بغیر مغربی طریقوں اور اصولوں کو اپنا لیں۔ پروفیسر محمد عثمان اپنی کتاب ’’فکرِ اسلامی کی تشکیلِ نو‘‘ میں لکھتے ہیں:
’’جو لوگ صدی، نصف صدی زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہوں، ان کی بات اور ہے، مگر جو قومیں اور تہذیبیں صدیوں تک یا تا قیامت صفحۂ ہستی پر اپنے آپ کو قائم دائم دیکھنے کی آرزومند اور دعویدار ہوں، ان کے لیے اور باتوں کے علاوہ ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ وہ ثبات اور تغیر کے باہمی ربط اور ان کی حقیقت کو واضح طور پر جانیں۔ زندگی نہ محض ثبات ہے اور نہ محض تغیر ہے ۔۔۔۔ مستقل اقدار کی مسلسل حفاظت کرنا اور بدلنے والے پہلوؤں میں تبدیلی قبول کرنا بقا و دوام کی شرطِ اول ہے۔‘‘3
حضرت علامہ اقبالؒ اسلام کی بقا اور استحکام کے پرجوش مبلغ اور علمبردار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس حقیقت کو محسوس کیا کہ جب تک مسلمانوں میں فکری سطح پر تعطل اور جمود کو دور نہ کیا جائے گا ان کا دنیا میں تری کرنا اور آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ علامہ اقبال کا مشہور و معروف انگریزی خطبہ
The Principle of Movement in the Structure of Islam
فقہ اسلامی کی تدوینِ نو کے ضمن میں عالمِ اسلام کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ سید نذیر نیازی نے اس انگریزی لیکچر کا ترجمہ ’’الاجتہاد فی الاسلام‘‘ کے نام سے کیا ہے۔ اقبال اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں ثبات اور تغیر دونوں پہلو موجود ہیں، لیکن ابدی اصول و قوانین سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تغیر کے ہر امکان کو رد کرتا ہے بلکہ حرکت اور تغیر ہی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں:
’’اسلام کے نزدیک حیات کی یہ روحانی اساس ایک قائم و دائم وجود ہے، جسے ہم اختلاف اور تغیر میں جلوہ گر دیکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی معاشرہ حقیقت مطلقہ کے اس تصور پر مبنی ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ثبات اور تغیر دونوں خصوصیات کا لحاظ رکھے۔ اس کے پاس کچھ تو اس قسم کے دوامی اصول ہونے چاہئیں جو حیاتِ اجتماعیہ میں نظم و انضباط قائم رکھیں، کیونکہ مسلسل تغیر کی اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہم اپنا قدم مضبوطی سے جما سکتے ہیں تو دوامی اصولوں ہی کی بدولت۔ لیکن دوامی اصولوں کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ اس سے تغیر اور تبدیلی کے جملہ امکانات کی نفی ہو جائے، اس لیے کہ تغیر وہ حقیقت ہے جسے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آیت ٹھہرایا ہے۔ اس صورت میں تو ہم اس شی کو، جس کی فطرت ہی حرکت ہے، حرکت سے عاری کر دیں گے۔‘‘4
پھر اقبال خود ہی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ
’’سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی ہیئتِ ترکیبی میں وہ کون سا عنصر ہے جو اس کے اندر حرکت اور تغیر قائم رکھتا ہے؟‘‘5
اور ساتھ ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ
’’اس کا جواب ہے، اجتہاد‘‘6
اقبال اجتہاد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
’’فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے وہ کوشش جو کسی قانونی مسئلے میں آزادانہ رائے قائم کرنے کے لیے کی جائے۔‘‘7
گویا روزمرہ زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے لیے قوانین وضع کرنے، اور ایسے مسائل جن میں شک و شبہ کا امکان ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے لیے قوانین مرتب کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ ارشاد رب العزت ہے:
’’جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔‘‘
اقبال اجتہاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ حضرت معاذؓ کو جب یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو ان کی روانگی کے وقت نبی کریمؐ نے ان سے دریافت کیا کہ اے معاذ! معاملات کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذؓ نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپؐ نے فرمایا، اگر کتاب اللہ سے تمہاری رہنمائی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ معاذؓ نے جواب دیا، تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ آپؐ نے فرمایا، اگر سنتِ رسول سے بھی رہنمائی میسر نہ ہو تو پھر؟ حضرت معاذؓ نے جواب دیا، تو پھر میں خود ہی کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔8
گویا نئے ماحول اور حالات میں نئی ضروریات اور تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنا ضروری ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کسی خاص معاملے میں خاموش ہوں تو پھر قرآن و سنت اور اجتماعی اسلامی مزاج کا لحاظ رکھنا قانون سازی کرتے ہوئے لازمی ہے۔
اگر اقبال کے خطبے ’’الاجتہاد فی الاسلام‘‘ کا دقتِ نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال اس خطبے میں خاص طور پر اسلامی ممالک اور ان میں پیش آنے والے مسائل سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خطبہ مختلف اسلامی ممالک میں اجتہادی کوششوں کے ضمن میں ایک Guideline کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ علامہ نے ترکوں کی اجتہادی کوششوں کی ہمیشہ تعریف کی ہے۔ اقبال ترکوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ
’’دراصل یہ صرف ترک ہیں جو اممِ اسلامیہ میں قدامت پرستی کے خواب سے بیدار ہو کر شعورِ ذات کی نعمت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ صرف ترک ہیں جنہوں نے ذہنی آزادی کا حق طلب کیا ہے اور جو ایک خیالی دنیا سے نکل کر اب عالمِ حقیقت میں آ گئے ہیں۔ لیکن یہ وہ تغیر ہے جس کے لیے انسان کو ایک زبردست دماغی اور اخلاقی کشاکش سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک طبعی امر تھا کہ ایک ہر لحظہ حرکت اور وسعت پذیر زندگی کی روز افزوں پیچیدگیوں سے انہیں نئے نئے حالات اور نئے نئے نقطہ ہائے نظر سے سابقہ پڑتا اور وہ ان اصولوں کی ازسرنو تعبیر پر مجبور ہو جاتے، جو ایک ایسی قوم کے لیے جو روحانی وسعتوں کی لذت سے محروم ہے، خشک بحثوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔‘‘9
علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ ترکوں نے ایک نہایت جرأتمندانہ اقدام کر کے اپنی سیاسی اور تہذیبی زندگی میں اپنی اجتہاد پسندی کا ثبوت دیا ہے اور زندگی کے نئے تقاضوں اور ضروریات کا ساتھ دیا ہے۔ اگر ہم یعنی ہندوستان کے لوگ بھی اسلامی اصول و قوانین کو موجودہ دور میں مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اپنے ذہنی اور فکری ورثے کا ازسرنو جائزہ لے کر اسے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے۔ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ
’’اگر اسلام کی نشاۃِ ثانیہ ناگزیر ہے، جیسا کہ میرے نزدیک قطعی طور پر ہے، تو ہمیں بھی ترکوں کی طرح ایک نہ ایک دن اپنے عقلی اور ذہنی ورثے کی قدر و قیمت کا جائزہ لینا پڑے گا۔‘‘10
اقبالؒ کی نظر میں اجتہاد ہی اسلام کی نشاۃِ ثانیہ کا ضامن ہے اور اسی کی مدد سے ہر دور میں اسلام اپنے پیروکاروں کو اپنے فیوض و برکات سے مستفید کر سکتا ہے۔ تاہم جہاں اقبال اجتہاد کی ضرورت و اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہیں اور عالمِ اسلام کو اجتہاد کی دعوت دیتے ہیں، وہاں انہیں اس بات کا بھی مکمل احساس ہے کہ اس معاملے میں ذرا سی زیادتی بھی مسلمانوں کو دین و ایمان سے دور پھینک سکتی ہے۔ آزادیٔ افکار کی گو اپنی اہمیت ہے، تاہم فکر و تدبر کا سلیقہ اس سے بھی اہم تر اور ضروری ہے کیونکہ ؎
ہو فکر اگر خام تو آزادیٔ افکار
انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ
بقول ڈاکٹر سید عبد اللہ:
’’علامہ اقبال کو فقہ اسلام کی تاریخ و تدوین کی اہمیت کا پورا احساس رہا۔ انہیں آج کے علمی و فکری ماحول میں اسلام کے اصولوں کی صداقت و افادیت ثابت کرنے پر اصرار رہا۔ بلاشبہ اس تدوینِ نو میں اجتہاد کی ضرورت اور بحث بھی آجاتی ہے، لیکن وہ اجتہاد کی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ تھے، کیونکہ اس کے لیے وافر اور فراواں اہلیت، تقوٰی اور تبحرِ علمی درکار ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس خدشے سے بھی غافل نہ تھے کہ بلا قید اور بلا شرط اجتہاد سے انتشار پیدا ہو کر ملت کا شیرازہ بکھر بھی سکتا ہے۔‘‘12
علامہ اقبال اپنے انگریزی خطبے میں رقمطراز ہیں:
’’ہم اس تحریک کا، جو حریت اور آزادی کے نام پر عالمِ اسلام میں پھیل رہی ہے، دل سے خیرمقدم کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، آزاد خیالی کی یہی تحریک اسلام کا نازک ترین لمحہ بھی ہے۔ آزاد خیالی کا رجحان بالعموم تفرقہ اور انتشار کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا نسلیت اور قومیت کے یہی تصورات جو اس وقت دنیائے اسلام میں کارفرما ہیں، اس وسیع مطمح نظر کی نفی بھی کر سکتے ہیں جس کی اسلام نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما حریت اور آزادی کے جوش میں، بشرطیکہ اس پر کوئی روک عائد نہ کی گئی، اصلاح کی جائز حدود سے تجاوز کر جائیں۔‘‘13
علامہ اقبال اگرچہ نئے فقہی فیصلوں کے حق میں تھے اور چاہتے تھے کہ زمانہ جدید کی مخصوص ضرورتوں کے تحت بنیادی ماخذ کی روشنی میں اسلامی اصول و قوانین کی تدوینِ نو کی جائے، تاہم ان کی اعتدال پسند طبیعت اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرتی تھی کہ اجتہاد اور تجدد کے نام پر ایسے تجاوزات عمل میں لائے جائیں جو اسلامی تعلیمات کی روح سے عاری ہوں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ کے نام ایک خط میں البانیہ کے مسلمانوں سے متعلق وہ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
’’میں نے سنا ہے کہ البانیہ کے مسلمانوں نے وضو اڑا دیا اور ممکن ہے نماز میں بھی کوئی ترمیم کی ہو۔‘‘14
اگرچہ اقبالؒ نے ترکوں کے اجتہاد کی ہر جگہ تعریف کی ہے مگر وہ اس اجتہاد کے ان پہلوؤں کا احتساب بھی کرتے ہیں جن سے اسلام کے بنیادی اصول و قوانین کے خلاف بغاوت کی بو آتی ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کہتے ہیں کہ ترکی کی نیشنلسٹ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ
’’ریاست ہی حیاتِ قومی کا بنیادی جزو ہے اور اس لیے باقی سب اجزا کی نوعیت اور وظائف بھی ریاست ہی سے متعین ہوں گے۔‘‘15
لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ
’’ذاتی طور پر مجھے اس سے اختلاف ہے کہ اسلام کی توجہ تمام تر ریاست پر ہے اور ریاست ہی کا خیال اس کے باقی تمام تصورات پر حاوی۔‘‘16
اقبال واضح طور پر کہتے ہیں کہ
’’دراصل ترک وطن پرستوں نے ریاست اور کلیسا کی تفریق کا اصول مغربی سیاست کی تاریخ افکار سے اخذ کیا ہے۔‘‘17
اقبال ایک ترک شاعر ضیا کی ان نظموں کا بھی سختی سے محاسبہ کرتے ہیں جن میں اس نے نماز، اذان اور تلاوتِ قرآن کو عربی کے بجائے ترکی زبان میں ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اقبال، ضیا کی نظم کے ایک بند کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
’’وہ سرزمین جہاں ترکی میں اذان دی جاتی ہے، جہاں نمازی اپنے مذہب کو جانتے اور سمجھتے ہیں، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ترکی زبان میں کی جاتی ہے، جہاں پر چھوٹا بڑا احکامِ الٰہیہ سے واقف ہے، اے فرزندِ ترکی! وہ ہے تیرا آبائی وطن۔‘‘18
حضرت علامہ، ترک شاعر ضیا کے اس اجتہاد کو، کہ نماز ترکی زبان میں ادا کی جائے، اذان ترکی زبان میں دی جائے، اور قرآن پاک کی ترکی زبان میں تلاوت کی جائے، مناسب خیال نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ
’’عربی کو ترکی سے بدلنے کا یہ خیال مسلمانانِ ہند کی غالب اکثریت کو ناگوار گزرے گا اور وہ اس کی مذمت کریں گے۔‘‘19
اپنی نظم کے ایک بند میں ضیا نے مساواتِ مرد و زن کے خیال کو بڑے پرجوش انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے عائلی نظام میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ عورت کے ساتھ عدل و انصاف ہو سکے۔ اس کے خیال میں جب تک عورت کو جائیداد میں آدھا حصہ ملے گا، اسے گواہی دینے کے معاملے میں بھی آدھا انسان ہی تصور کیا جائے گا، ترک شاعر ضیا کہتا ہے کہ
’’جب تک عورتوں کی صحیح قدر و قیمت کا احساس نہیں ہو گا، حیاتِ ملی نامکمل رہے گی۔ اہل و عیال کی پرورش میں عدل و انصاف پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے لیے تین چیزیں ہیں جن میں مساوات ناگزیر ہے: طلاق میں، علیحدگی میں، وراثت میں۔‘‘20
اقبال، ترک شاعر کے ان خیالات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
’’رہا ترکی شاعر کا مطالبہ، سو میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کے قانونِ عائلہ سے کچھ بہت زیادہ واقف نہیں۔ وہ نہیں سمجھتا کہ قرآن پاک نے وراثت کے بارے میں جو قاعدہ نافذ کیا ہے اس کی معاشی قدر و قیمت کیا ہے۔ شریعتِ اسلامی میں نکاح کی حیثیت ایک عقد اجتماعی کی ہے۔ اور بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ بوقتِ نکاح شوہر کا حقِ طلاق بعض شرائط کی بنا پر خود اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یوں امرِ طلاق میں تو مرد و زن کے درمیان مساوات قائم ہو جاتی ہے۔ رہی وہ اصلاح جو شاعر نے قانونِ وراثت میں تجویز کی ہے، سو اس کی بنا غلط فہمی پر ہے۔ اگر قانون کے کچھ حصوں میں مساوات نہیں کی گئی تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ خیال تعلیماتِ قرآن کے منافی ہے۔ قرآن مجید کا صاف و صریح ارشاد ہے ’’ولھن مثل الذی علیھن (بقرہ ۲۲۸) لہٰذا لڑکی کا حصہ متعین ہوا تو کسی کمتری کی بنا پر نہیں بلکہ ان فوائد کے پیشِ نظر جو معاشی اعتبار سے اسے حاصل ہیں۔‘‘21
اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ اقبال عصری تقاضوں کے پیشِ نظر قوانینِ اسلامی کی تدوینِ نو کے قائل ہیں اور اسے وقت کی ضرورت خیال کرتے ہیں، تاہم وہ بے اعتدالی اور کسی بھی معاملے میں کسی کی بھی کورانہ تقلید کے ہرگز قائل نہیں۔ اقبال اسلام کے بنیادی اور ابدی ماخذ میں کسی قسم کی بھی تبدیلی کے حق میں نہیں۔ ان کے نزدیک بنیادی ماخذ ہمارے ماضی کا شاندار علمی ورثہ ہیں، جن سے منہ موڑ کر اور انہیں پسِ پشت ڈال کر ہم کبھی بھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلامی قوانین کے لیے چار بنیادی ماخذ ہیں: (۱) قرآن (۲) حدیث (۳) قیاس (۴) اجماع۔
(۱) قرآن مجید
قرآن کو اسلامی قوانین کا اولین ماخذ قرار دیا جاتا ہے لیکن قرآن قانونی ضابطوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ معاملاتِ زندگی سے متعلق عام لیکن بنیادی اصولوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ
’’قرآن کوئی قانونی ضابطہ نہیں، اس کا حقیقی منشا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے عرض کر آئے ہیں، یہ ہے کہ ذہنِ انسانی میں اس تعلق کا، جو اسے کائنات اور خالقِ کائنات سے ہے، اعلیٰ اور بہترین شعور پیدا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں قانونی نوعیت کے کچھ عام اصول اور قواعد و ضوابط موجود ہیں ۔۔۔‘‘22
اقبالؒ ملتِ اسلامیہ کی توجہ قرآن پاک کے اس خاص انداز اور اسلوب کی طرف دلا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جامعیت اور ابدیت اسی میں ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے بنیادی اصول فراہم کر دیے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر زمانے اور ہر دور میں نئی ضروریات اور بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ گویا اس طرح اگر ہم غور کریں تو قرآن اپنے اندر ایک حرکی تصورِ حیات رکھتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں:
’’ظاہر ہے کہ جس کتاب کا مطمح نظر ایسا ہو گا اس کی روش ارتقا کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟‘‘23
حرکی تصورِ حیات کا یہ مطلب ہیں کہ اس میں ثبات کا کوئی بھی پہلو نہیں، بلکہ اقبال کے تصورِ حیات میں ایک Element of Permanence بھی ہے جس کا دمن کبھی بھی ہاتھ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اقبال فرماتے ہیں:
’’ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تو یہ کہ زندگی محض تغیر ہی نہیں، اس میں حفظ و ثبات کا ایک عنصر بھی موجود ہے۔‘‘24
اور پھر اقبال بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ
’’تعلیماتِ قرآن کی یہی وہ جامعیت ہے جس کا لحاظ رکھتے ہوئے جدید عقلیت کو اپنے ادارات کا جائزہ لینا ہو گا۔ دنیا کی کوئی قوم اپنے ماضی سے قطع نظر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ ان کا ماضی ہی تھا جس سے ان کی موجودہ شخصیت متعین ہوئی۔‘‘25
(۲) حدیث
قرآن پاک کے بعد اسلامی قوانین کا سب سے بڑا ماخذ احادیثِ رسولؐ ہیں۔ ہمیں قانونی حیثیت کی حامل احادیث اور دوسری احادیث میں امتیاز کرنا ہو گا۔ بقول علامہ اقبال:
’’جہاں تک مسئلہ اجتہاد کا تعلق ہے، ہمیں چاہیے کہ ان احادیث کو، جن کی حیثیت سراسر قانونی ہے، ان احادیث سے الگ رکھیں جن کا قانون سے کوئی تعلق نہیں۔‘‘26
احادیث کی قانونی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال، حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے بہت سے احکام عربوں کی مقامی روایات اور ان کے قومی مزاج کو سامنے رکھ کر دیے تھے، جن کی اطاعت دوسری قوموں کے افراد کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کا مزاج، روایات اور ماحول عربوں سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علامہ اپنے انگریزی خطبے میں شاہ ولی اللہ کے حوالے سے رقمطراز ہیں:
’’انبیاء کا عام طریقِ تعلیم تو یہی ہے کہ وہ جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں ان پر اسی قوم کے رسم و رواج اور عادات و خصائص کے مطابق شریعت نازل کی جاتی ہے۔ لیکن جس نبی کے سامنے ہمہ گیر اصول ہیں، اس پر نہ تو مختلف قوموں کے لیے مختلف اصول نازل کیے جائیں گے، نہ یہ ممکن ہے کہ وہ ہر قوم کو اپنی اپنی ضروریات کے لیے الگ الگ اصولِ عمل متعین کرنے کی اجازت دے۔ وہ کسی ایک قوم کی تربیت کرتا اور پھر ایک عالمگیر شریعت کی تشکیل میں اس سے تمہید کا کام لیتا ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں وہ اگرچہ انہی اصولوں کو حرکت دیتا ہے جو ساری نوعِ انسانی کی حیاتِ اجتماعیہ میں کارفرما ہیں۔ پھر بھی ہر معاملے اور ہر موقع پر عملاً ان کا اطلاق اپنی قوم کی مخصوص عادات کے مطابق ہی کرتا ہے۔ لہٰذا اس طرح جو احکام وضع ہوتے ہیں (مثلاً تعزیرات) ایک لحاظ سے اسی قوم کے لیے مخصوص ہوں گے۔ پھر چونکہ احکام مقصود بالذات نہیں، اس لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو آئندہ نسلوں کے لیے بھی واجب ٹھہرایا جائے۔‘‘27
علامہ اقبالؒ امام ابوحنیفہؒ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنی فقہ میں ایسی احادیث کا خاص طور پر استعمال ہیں کیا جن کا ایک خاص زمانے سے اور لوگوں کے مزاج سے تعلق تھا۔ علامہ فرماتے ہیں:
’’شاید یہی وجہ تھی کہ امام ابوحنیفہؒ نے، جو اسلام کی عالمگیر نوعیت کو خوب سمجھ گئے تھے، ان احادیث سے اعتنا نہیں کیا۔‘‘28
یہاں ’’ان احادیث‘‘ سے مراد ایسی احادیث ہیں جن کا (تعلق) مخصوص زمانے سے اور اس زمانے کے لوگوں کے مخصوص عادات و کردار اور مزاج سے تھا۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں:
’’اگر آزادیٔ اجتہاد کی وہ تحریک جو اس وقت دنیائے اسلام میں پھیل رہی ہے، احادیث کو بلا جرح و تنقید قانون کا ماخذ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس سے اہل سنت والجماعت کے ایک امام الائمہ ہی کی پیروی مقصود ہے۔‘‘29
یہاں بعض لوگوں کو یہ احتمال گزر سکتا ہے کہ اقبال، خدانخواستہ، احادیث کو کم اہمیت دیتے تھے یا یہ کہ وہ منکرِ حدیث تھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اگر اقبال کا ایسا خیال ہوتا تو وہ قانون سازی کے عمل میں احادیث کا قرآن کے بعد ذکر ہی نہ کرتے۔ اقبالؒ تو محض Indiscriminate use of Traditions کے خلاف ہیں، ورنہ تو حضرت علامہ رقمطراز ہیں:
’’سب سے بڑی خدمت جو محدثین نے شریعتِ اسلامیہ کی سرانجام دی ہے، یہ ہے کہ انہوں نے مجرد غور و فکر کے رجحان کو روکا اور اس کی بجائے ہر مسئلے کی الگ تھلگ شکل اور انفرادی حیثیت پر زور دیا۔‘‘30
اقبالؒ قانون سازی کے عمل میں احادیث کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
’’احادیث کا مطالعہ اگر اور زیادہ گہری نظر سے کیا جائے اور ہم ان کا استعمال یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ وہ کیا روح تھی جس کے تحت آنحضرتؐ نے احکامِ قرآن کی تعبیر فرمائی، تو اس سے ان قوانین کی حیاتی قدر و قیمت کے فہم میں اور بھی آسانی ہو گی جو قرآن پاک نے قانون کے متعلق قائم کیے ہیں۔ پھر یہ ان اصولوں کی حیاتی قدر و قیمت ہی کا پورا پورا علم ہے جس کی بدولت ہم اپنی فقہ کے بنیادی ماخذ کی ازسرنو تعبیر اور ترجمانی کر سکتے ہیں۔‘‘31
(۳) اجماع
فقہ اسلامی کا تیسرا بڑا ماخذ اجماع ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی اپنی کتاب ’’مسئلہ اجتہاد‘‘ میں اجماع کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
’’اصطلاح کی رو سے اجماع اس سے تعبیر ہے کہ مجتہدین اور اربابِ حل و عقد آنحضرتؐ کے بعد کسی عصر و زمانہ میں کسی امرِ دینی پر متفق ہو جائیں ۔۔۔۔ جب کوئی مسئلہ مخصوص اسباب کی بنا پر ابھرے اور ائمہ و مجتہدین کے سامنے آئے تو اس کے فیصلہ میں اس دور کے مجتہدین و اربابِ اختیار میں اختلافِ رائے نہ پایا جاتا ہو۔‘‘32
علامہ کو اس بات پر افسوس ہے کہ ’’اجماع‘‘ باوجود اسلامی قانون سازی کا ایک بہت بڑا اور اہم ماخذ ہونے کے، علمی صورت اختیار نہ کر سکا۔ اقبال کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں مطلق العنان سلطنتیں قانون سازی کی مجالس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے خطرہ تصور کرتی تھیں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ
’’اموی اور عباسی خلفاء کا فائدہ اسی میں تھا کہ اجتہاد کا حق بحیثیت افراد مجتہدین ہی کے ہاتھ میں رہے، اس کی بجائے کہ اس کے لیے ایک مستقل مجلس قائم ہو، جو بہت ممکن ہے انجام کار ان سے بھی زیادہ طاقت حاصل کر لیتی۔‘‘33
حضرت علامہؒ اس بات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ اب اسلامی ممالک میں مجالس قانون ساز اور جمہوریت کا فروغ ہو رہا ہے اور اجماع کے لیے بہتر صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اقبال موجودہ زمانہ میں اجماع کی ممکنہ صورت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
’’مذاہبِ اربعہ کے نمائندے جو سردست فردًا فردًا اجتہاد کا حق رکھتے ہیں، اپنا یہ حق مجالسِ تشریعی کو منتقل کر دیں گے۔ یوں بھی مسلمان چونکہ متعدد فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے ممکن بھی ہے تو اس وقت اجماع کی یہی شکل۔ مزید برآں غیر علماء بھی، جو ان امور میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس میں حصہ لے سکیں گے۔ میرے نزدیک یہی ایک طریقہ ہے جس سے کام لے کر ہم زندگی کی اس روح کو، جو ہمارے نظاماتِ فقہ میں خوابیدہ ہے، ازسرنو بیدار کر سکتے ہیں۔ یونہی اس کے اندر ایک ارتقائی مطمح نظر پیدا ہو گا۔‘‘34
اقبالؒ دورِ جدید میں ترکوں کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے منصبِ اجتہاد کو افراد کی ایک جماعت بلکہ منتخب شدہ مجلسِ قانون ساز کے سپرد کر دیا۔ اقبال کے نزدیک ترکوں کا یہ اقدام قابلِ استحسان ہے، لیکن یہاں ایک خدشہ اقبال کے ذہن میں جنم لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو افراد منتخب ہو کر اسمبلی میں آئیں اور قانون سازی کریں، وہ اسلامی اصول و قوانین سے نابلد ہوں۔ چنانچہ اقبال کی نظر میں:
’’اس قسم کی مجالس شریعت کی تعبیر میں بڑی بڑی شدید غلطیاں کر سکتی ہیں۔ ان غلطیوں کے ازالے یا کم سے کم امکان کی صورت کیا ہو گی؟‘‘35
اقبال کے نزدیک اس قسم کی غلط تعبیرات کی روک تھام کا واحد طریقہ یہ ہے کہ علماء کا ایک مشاورتی بورڈ قائم کیا جائے جو اسمبلی کی معاونت اور رہنمائی کر سکے۔ اقبال لکھتے ہیں:
’’انہیں چاہیے، مجالسِ قانون ساز میں علماء کو بطور ایک مؤثر جزو شامل تو کر لیں، لیکن علماء بھی ہر امرِ قانون میں آزادانہ بحث و تمحیص اور اظہارِ رائے کی اجازت دیتے ہوئے اس کی رہنمائی کریں۔ بایں ہمہ شریعتِ اسلامی کی غلط تعبیرات کا سدباب ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ بحالتِ موجودہ بلادِ اسلامیہ میں فقہ کی تعلیم جس نہج پر ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ فقہ کا نصاب مزید توسیع کا محتاج ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جدید فقہ کا مطالعہ بھی باحتیاط اور سوچ سمجھ کر کیا جائے۔‘‘36
(۴) قیاس
اقبالؒ کے نزدیک اجتہاد کا چوتھا اور آخری ماخذ قیاس ہے۔ قانون سازی میں مماثلتوں کی بنا پر استدلال سے کام لینا قیاس کہلاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں:
’’چوتھا ماخذ قیاس ہے، یعنی قانون سازی میں مماثلتوں کی بنا پر استدلال سے کام لینا۔‘‘37
قیاس کرتے ہوئے اسلام کے بنیادی تقاضوں اور روح کو پیشِ نظر رکھا جاتا ہے اور ان کی روشنی میں نئے احکام اور اصول و قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ قیاس کی تین صورتیں ہیں:
(۱) کوئی ایسا حکم جو قرآن مجید میں ہو، اس پر کسی دوسرے غیر مذکور حکم کو قیاس کرنا۔
(۲) کوئی ایسا حکم جو حدیث میں ہو، اس پر کسی غیر مذکور حکم کو قیاس کرنا۔
(۳) کوئی ایسا حکم جو اجماع سے ثابت ہو، اس پر قیاس کرنا۔
اقبال کا واضح نقطہ نظر یہ ہے کہ قیاس صرف اسی موقع پر عمل میں آئے گا جہاں قرآن، سنتِ رسولؐ اور اجماع رہنمائی نہ کرے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ
’’قیاس کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر کام میں لایا جائے تو، جیسا کہ امام شافعی کا ارشاد ہے، وہ اجتہاد ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور اس لیے نصوصِ قرآنی کی حدود کے اندر ہمیں اس کے استعمال کی پوری پوری آزادی ہونی چاہیے۔ پھر بحیثیت ایک اصولِ قانون اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے ہو جاتا ہے کہ بقول قاضی شوکانی زیادہ تر فقہاء اس امر کے قائل تھے کہ حضور رسالتمابؐ کی حیاتِ طیبہ میں بھی قیاس سے کام لینے کی اجازت تھی۔‘‘38
علامہؒ زندگی کو ایک مسلسل تخلیقی بہاؤ قرار دیتے ہیں۔ اس میں جمود، سکونت اور ٹھہراؤ نہیں بلکہ روانی، حرکت اور ارتقا اس کی فطرت ہے۔ اس لیے ہر زماں اپنے قانونی نظام کا ازسرنو جائزہ لینا اور اسے Reconstruct کرنا لازمی ہے۔ زندگی کے اندر بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی وہی طاقت ہے جو بیج میں درخت بننے کی قوت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر خالد مسعود اپنی کتاب ’’اقبال کا تصورِ اجتہاد‘‘ میں اجتہاد کے تصور کے حوالے سے رقمطراز ہیں:
’’یہ بحرِ حیات کی موجوں کا اضطراب ہے۔ رمِ زندگی ہے، ولولۂ شوق ہے۔ لذتِ پرواز ہے۔ جراتِ نمو ہے۔ یہ طوفانِ زندگی سے نبرد آزمائی کا عزم ہے۔ یہ تندیٔ باد مخالف کے تھپڑوں کا مقابلہ کرنے کا شاہینی شکوہ ہے۔ عزیمت کی راہ ہے۔ نغمۂ تارِ حیات ہے اور کشمکشِ انقلاب ہے۔‘‘39
گویا زندگی ہر دم منزلِ نو کی طرف گامزن ہے۔ جمود اور سکون اس کی سرشت میں نہیں۔ تغیر و ارتقا اس کے لیے وجۂ ثبات ہے۔ تو ضرورت ہے کہ رمِ آہو کی مانند ہر دم نئے راستوں اور راہوں پر گامزن حیاتِ مسلسل کے لیے کچھ ایسے ابدی اصول و قوانین ہوں جو زندگی کے تغیرات کی رہنمائی کر سکیں۔ حضرت علامہ اقبالؒ نے اپنے خطبہ ’الاجتہاد فی الاسلام‘‘ میں اسی امر کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم جدید دور میں نئے حالات اور ماحول کی روشنی میں زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر اجتہادی فکر کا پیدا کرنا ازبس ضروری ہے۔ حضرت علامہ کا خطبہ ’’الاجتہاد فی الاسلام‘‘ ممالک اسلامیہ کے لیے ایک Guideline ہے جس سے استفادہ کر کے مسلمان نہ صرف اپنے آپ کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں بلکہ ترقی یافتہ قوموں کی صف میں اپنا ایک منفرد مقام بھی بنا سکتے ہیں۔
حوالہ جات
- ’’فکرِ اقبال‘‘ ص ۱۴۹ ۔ خلیفہ عبد الحکیم ۔ بزمِ اقبال، لاہور ( ۱۹۶۸ء) ۔
- ’’تشکیلِ جدید الٰہیات اسلامیہ‘‘ ص ۲۲۳ ۔ ترجمہ: سید نذیر نیازی ۔ بزمِ اقبال، لاہور (۱۹۸۶ء) ۔
- ’’فکرِ اسلامی کی تشکیلِ نو‘‘ ص ۱۵۱، ۱۵۲ ۔ پروفیسر محمد عثمان ۔ سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور (۱۹۸۷ء) ۔
- ’’تشکیلِ جدید الٰہیاتِ اسلامیہ‘‘ ص ۲۲۷، ۲۲۸۔
- ایضاً ص ۲۲۸
- ایضاً۔
- ایضاً۔
- ’’فکرِ اسلامی کی تشکیلِ نو‘‘ ص ۱۵۳، ۱۵۴۔
- ’’تشکیلِ جدید الٰہیاتِ اسلامیہ‘‘ ص ۲۵۰۔
- ایضاً ص ۲۳۶۔
- ’’کلیاتِ اقبال‘‘ ۔ اقبالؒ ۔ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور (۱۹۸۲ء)۔
- ’’مطالعۂ اقبال کے چند نئے رخ‘‘ ص ۱۲۱، ۱۲۲ ۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ ۔ بزمِ اقبال لاہور (۱۹۸۲ء)۔
- ’’تشکیلِ جدید الٰہیاتِ اسلامیہ‘‘ ص ۲۵۱، ۲۵۲۔
- ’’اقبال نامہ‘‘ (حصہ اول) ص ۱۴۴ ۔ محمد اقبال ۔ مرتبہ: شیخ عطاء اللہ ۔ ناشر: شیخ محمد اشرف، لاہور۔
- ’’تشکیلِ جدید الٰہیاتِ اسلامیہ‘‘ ص ۲۳۶۔
- ایضاً ص ۲۳۷۔
- ایضاً ص ۲۳۹۔
- ایضاً ص ۲۴۸۔
- ایضاً۔
- ایضا۔ ص ۲۴۹۔
- ایضاً ص ۲۶۱، ۲۶۲۔
- ایضاً ص ۲۵۵، ۲۵۶۔
- ایضاً ص ۲۵۷۔
- ایضاً۔
- ایضاً ص ۲۵۷، ۲۵۸۔
- ایضاً ص ۲۶۴۔
- ایضاً ص ۲۶۵، ۲۶۶۔
- ایضاً۔
- ایضاً۔ ص ۲۶۶، ۲۶۷۔
- ایضاً۔
- ایضاً۔
- ’’مسئلہ اجتہاد‘‘ ص ۱۰۱، ۱۰۲ ۔ مولانا محمد حنیف ندوی ۔ ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، لاہور (۱۹۸۳ء)۔
- ’’تشکیلِ جدید الٰہیاتِ اسلامیہ‘‘ ص ۲۶۷، ۲۶۸۔
- ایضاً ص ۲۶۸۔
- ایضاً ص ۲۷۰۔
- ایضاً ص ۲۷۱۔
- ایضاً۔
- ایضاً ص ۲۷۴۔
- ’’اقبال کا تصورِ اجتہاد‘‘ ص ۲۳۶ ۔ ڈاکٹر خالد مسعود ۔ مطبوعاتِ حرمت، راولپنڈی (۱۹۸۵ء)۔
اسلام اور مغرب کی کشمکش ۔ برطانوی ولی عہد کی نظر میں
ادارہ
(آکسفورڈ (برطانیہ) میں اسلامی تعلیمات کے مطالعہ کا مرکز ’’آکسفورڈ سنٹر فار اسلامک اسٹڈیز‘‘ کے نام سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی اور نگرانی میں قائم ہے جس کے ڈائریکٹر معروف دانشور ڈاکٹر فرحان احمد نظامی ہیں جو برصغیر کے نامور محقق و مصنف جناب پروفیسر خلیق احمد نظامی کے فرزند اور صاحبِ فکر و بصیرت استاذ ہیں۔ برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس نے ستمبر ۱۹۹۳ء کے دوران اس سنٹر میں اسلام اور مغرب کے تعلقات کے حوالہ سے ایک تقریب میں مفصل خطاب کیا، ہم اس خطاب کا مکمل متن اور مصدقہ اردو ترجمہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ان شاء اللہ العزیز، سرِدست ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور میں اس کا شائع شدہ خلاصہ ادارہ ترجمان القرآن کے شکریہ کے ساتھ نذرِ قارئین ہے۔ ادارہ)
عالمِ اسلام اور مغربی دنیا کے درمیان روابط آج جتنی اہمیت رکھتے ہیں پہلے کبھی نہ رکھتے تھے۔ آج کی باہم منحصر دنیا میں دونوں کو ساتھ رہنے اور ساتھ کام کرنے کی ضرورت شدید ہے لیکن دونوں کے درمیان سنگین غلط فہمیاں موجود ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مغرب کی غلط فہمیوں کی وجہ اسلام اور مسلمانوں سے ناواقفیت نہیں، آخر مسلمان ہمارے ہی آس پاس رہتے ہیں، خود برطانیہ میں پانچ سو مسجدیں ہیں اور ۱۹۷۶ء کے ’’فیسٹیول آف اسلام‘‘ کی یادیں ابھی تازہ ہیں۔
نوے کے عشرے میں، سرد جنگ کے بعد، امن کے امکانات اس صدی میں کسی دوسرے دور سے زیادہ ہونا چاہیے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق یوگوسلاویہ میں، صومالیہ، انگولا اور سوڈان میں، اور سابق سوویت جمہوریتوں میں نفرت اور تشدد نے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بوسنیا کے مسلمانوں پر خوفناک مظالم نے اس خوف اور بداعتمادی کو نئی زندگی دی ہے جو ہماری دو دنیاؤں کے درمیان پہلے سے موجود ہیں۔
کشمکش اور تنازع کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ پا رہے ہوں۔ ہمیں باہمی خوف اور انتشار کے ایک نئے دور میں محض اس لیے نہ داخل ہو جانا چاہیے کہ حکومتیں، عوام، مذاہب اور مختلف طبقات ایک سکڑتی ہوئی دنیا میں پُراَمن زندگی گزارنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ جو مشترک امور اسلام اور مغرب کو قریب کرتے ہیں، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں جو دونوں کو دور کرتے ہیں۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی اہلِ کتاب ہیں۔ اسلام اور عیسائیت ایک خدا پر، اس دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے پر، اپنے اعمال کی جوابدہی پر اور اخروی زندگی پر یقین رکھنے میں یکساں ہیں۔ احترام، علم و عدل، محروموں سے حسنِ سلوک، اور خاندانی زندگی کی اہمیت ہماری مشترک اقدار ہیں۔ اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا، یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔
مسئلہ کی ایک جڑ یہ ہے کہ ہماری چودہ سو سال کی تاریخ باہمی کشمکش اور تصادم کی تاریخ ہے۔ اس نے خوف اور بد اعتمادی کی ایسی روایت کو جنم دیا ہے کہ ہم تاریخ کو متضاد نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ مغرب کے سکول کے طالب علموں کے لیے صلیبی جنگوں کے دو سو برس اس دلیرانہ جدوجہد کی داستان ہیں جو یورپ کے بچے بچے نے یروشلم کو ’’کافر‘‘ مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے کی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے صلیبی جنگیں مغرب کے ’’کافر‘‘ سپاہیوں کے ظلم و ستم اور لوٹ کھسوٹ کی داستان ہیں جس کی بدترین علامت وہ قتل و غارت ہے جو ۱۰۹۹ء میں اسلام کے تیسرے مقدس ترین شہر کو واپس لیتے ہوئے صلیبیوں نے برپا کی۔ ہمارے لیے مغرب میں ۱۴۹۲ء وہ اہم سال ہے جب کولمبس نے امریکہ کی نئی دریافت کی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک المیہ کا سال تھا جب فرڈیننڈ اور ازابیلا کے آگے غرناطہ سرنگوں ہوا اور یورپ میں مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا، اس کی تاریخ اور اس میں اپنے کردار کے بارے میں ہم دوسروں کا نقطۂ نظر نہیں سمجھ پاتے۔
اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم ماضی میں اسلام کو فاتح کی حیثیت سے ایک خطرہ سمجھتے رہے، اور اب جدید دور میں اسے عدمِ رواداری، انتہا پسندی اور تشدد کا منبع تصور کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ۱۴۵۳ء میں جب قسطنطنیہ سلطان محمد کے آگے سرنگوں ہو گیا اور ۱۵۲۹ء اور ۱۶۸۳ء میں جب ترکی وی آنا کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے تو یورپ کے حکمرانوں پر کیوں لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ عثمانیوں کے دور میں بھی بلقان میں ظلم کی ایسی مثالیں سامنے آئیں جو مغرب کے شعور پر ثبت ہو گئیں، مگر یہ یکطرفہ نہ تھا۔ ۱۷۹۸ء میں مصر پر نپولین کے حملہ اور اس کے بعد انیسویں صدی کی فتوحات نے حالات کو پلٹ دیا، اور تقریباً تمام عرب دنیا مغربی طاقتوں کے استعمار کا شکار ہو گئیں۔ سلطنتِ عثمانیہ کے زوال کے ساتھ اسلام پر یورپ کی فتح مکمل ہو گئی۔
فتوحات کا دور تو گزر گیا لیکن اب بھی اسلام کے بارے میں ہمارا رویہ درست نہیں ہوا ہے۔ ہماری نظروں میں جو اسلام ہے وہ یہ ہے جسے انتہا پسندوں نے ’’اغوا‘‘ کیا ہوا ہے۔ مغرب میں ہم میں سے بیشتر، اسلام کو لبنان کی خانہ جنگی اور شرقِ اوسط کے انتہا پسند گروہوں کی جانب سے قتل اور بم پھینکنے کی وارداتوں، جسے اب عام طور پر اسلامی بنیاد پرستی کہہ دیا جاتا ہے، کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ غیر معمولی انتہاؤں کو معمول قرار دے کر ہم نے اسلام کے بارے میں اپنی رائے کو مسخ کر دیا ہے، یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم برطانوی معاشرے میں قتل، عصمت دری، نشہ بازی اور بچوں پر ظلم کے واقعات سے یہاں کی زندگی کے بارے میں رائے قائم کریں۔ انتہاؤں کا وجود کہاں نہیں ہوتا، لیکن اگر انہیں کسی معاشرے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی بنیاد بنا لیا جائے تو حقائق مسخ ہو جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر، اس ملک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٍشرعی قوانین ظالمانہ ہیں، اور ہمارے اخبارات بھی ان تعصبات کو بہت شوق سے آگے بڑھاتے ہیں۔ حقیقت یقیناً اس سے بہت مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہاتھ کاٹنے جیسے انتہائی اقدامات پر شاذ ہی عمل ہوتا ہے۔ اسلامی قانون کی روح اور راہنما اصول اگر قرآن سے براہ راست اخذ کیے جائیں تو ہمدردی اور انصاف ہونا چاہیے۔ اپنا فیصلہ دینے سے پہلے ہمیں ان کے عملی نفاذ کی صورتحال کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہئیں۔ اس وقت خود اسلامی دنیا میں زیر بحث ہے کہ اسلامی قانون کہاں تک آفاقی یا ابدی ہے، اور کہاں تک اس میں نفاذ کے حوالے سے تبدیلی اور ارتقا ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلام اور بعض اسلامی ممالک کے رسوم و رواج میں بھی فرق کرنا چاہیے۔
مغرب کا ایک واضح تعصب اسلامی معاشرہ میں خواتین کے مقام کے حوالے سے ہے۔ حالانکہ مصر، ترکی اور شام نے سوئٹزرلینڈ سے بہت پہلے ہی عورتوں کو ووٹ کا حق دیا۔ چودہ سو سال پہلے قرآن نے خواتین کو جائیداد، وراثت، تجارت اور طلاق کی صورت میں بعض تحفظات کے حقوق دیے، خواہ ان پر ہر جگہ عمل نہ کیا گیا ہو۔ برطانیہ میں یہ حقوق میری دادی اور ان کے اہل خاندان کے لیے بھی نئے تھے۔ خالدہ ضیا اور بے نظیر بھٹو اپنے روایتی معاشروں میں اس وقت وزیراعظم بنیں جب برطانیہ کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیراعظم کا انتخاب ہوا۔
اسلامی معاشرے میں عورت خودبخود دوسرے درجے کی شہری نہیں بن جاتی۔ بہت زیادہ قدامت پسند ملک میں عورت کے مقام کو دیکھ کر اسلامی معاشروں میں اس کے مقام کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ پردہ کا رواج بھی تمام اسلامی ممالک میں نہیں ہے۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ پردہ کی ابتدا بازنطینی اور ساسانی ادوار میں ہوئی، پیغمبرؐ اسلام کے دور سے نہیں۔ بعض مسلمان خواتین سرے سے پردہ نہیں کرتیں، بعض نے اسے ترک کر دیا ہے۔ حالیہ دور میں بعض نے، خصوصاً نوجوان نسل نے پردہ اختیار کیا ہے تو اپنی اسلامی شناخت کے اظہار کے لیے۔
ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسلامی دنیا ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ اگر ہم یہ جاننے سے انکار کر دیں کہ اسلامی دنیا یورپ کی مادی ثقافت کو اپنی اقدار اور طرزِ حیات کے لیے خطرہ تصور کرتی ہے تو اس سے ہمیں نقصان زیادہ اور فائدے کم ہوں گے۔ اسی طرح بعض اسلامی اقدار کے بارے میں یورپی لوگوں کے ردعمل کا اسلامی دنیا میں سمجھا جانا ضروری ہے۔
ہمیں بنیادی پرستی کے لیبل کے بارے میں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ ہمیں احیائے اسلام کے ان علمبرداروں میں جو اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ان جنونی انتہا پسندوں میں فرق کرنا چاہیے جو اس تعلق کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ احیائے اسلام کو تحریک درحقیقت اس احساس سے ملی ہے کہ مغرب نے جو کچھ مادی حوالے سے دیا ہے وہ ناکافی ہے اور حقیقی معنوں میں زندگی کو تسکین دراصل اسلامی عقیدہ ہی سے ملتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انتہا پسندی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، عیسائیت سمیت یہ دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کی عظیم اکثریت، جو ذاتی طور پر نیک ہے، سیاست میں معتدل روش اختیار کرتی ہے۔ پیغمبرِ اسلامؐ خود انتہا پسندی کو ناپسند کرتے تھے، یہ مذہب اعتدال کا مذہب ہے۔
ہماری تہذیب اور تمدن پر اسلامی دنیا کے جو احسانات ہیں ہم ان سے بڑی حد تک ناواقف ہیں۔ وسطِ ایشیا سے بحرِ اوقیانوس کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی اسلامی دنیا علم و دانش کا گہوارہ تھی۔ لیکن اسلام کو ایک دشمن مذہب اور اجنبی تہذیب قرار دینے کی وجہ سے ہمارے اندر اپنی تاریخ پر اس کے اثرات کو نظرانداز کرنے یا مٹانے کا رجحان رہا۔ ہم نے اسپین میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی تہذیب کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ مغرب میں احیائے تہذیب کی تحریک پر مسلم اسپین نے گہرے اثرات ڈالے۔ یہاں علوم کی ترقی سے یورپ نے صدیوں بعد تک فائدہ اٹھایا۔ دسویں صدی میں قرطبہ یورپ کا مہذب ترین شہر تھا۔ حکمران کی لائبریری میں موجود چار لاکھ کتب پورے یورپ کی لائبریریوں کی کتب کی تعداد سے زائد تھیں۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ غیر مسلم یورپ سے چار سو سال پہلے مسلمانوں نے چین سے کاغذ بنانے کی مہارت حاصل کر لی تھی۔
جدید یورپ آج جن باتوں پر فخر کرتا ہے اس نے مسلم اسپین سے حاصل کیں۔ سفارت کاری، آزاد تجارت، کھلی سرحدیں، علمی تحقیق کے طریقے، ایٹیکیٹ، فیشن، ہسپتال، ادویات، سب کچھ اس عظیم شہر سے ہی آتے تھے۔ اپنے وقت میں اسلام رواداری کا مذہب تھا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے عقائد کے مطابق عمل کی آزادی دی اور ایسی مثال پیش کی جس پر بدقسمتی سے کئی صدیوں تک یورپ عمل نہ کر سکا۔ یہ بات حیرتناک ہے کہ اسلام کو یورپ میں، پہلے اسپین میں اور پھر بلقان میں، اتنا طویل عرصہ دخل رہا۔ اس نے ہماری تہذیب کی تعمیر میں، جسے ہم اکثر غلطی سے صرف مغربی قرار دیتے ہیں، اپنا حصہ ادا کیا۔ دراصل اسلام ہمارے ماضی اور حال کا حصہ ہے، اس نے جدید یورپ کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کیا ہے، اسلام ہمارا ورثہ ہے۔
اس دنیا میں مل جل کر رہنے کے لیے اسلام کے دامن میں وہ کچھ ہے جو اب عیسائیت کے پاس نہیں ہے۔ اسلام کا کائنات اور انسان کا تصور ایک جامع، ہمہ گیر تصور ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اسلام میں پوری زندگی ایک اکائی ہے۔ مغرب کی ساری ترقی یک رخی ہے، اگر ہم نے زندگی کے ہمہ جہتی انداز کو نہ سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس دھارے میں بہہ جائیں جہاں ہمارا علم ہمیں محض کارِ جہاں سکھائے اور ہم دنیا کے حسن اور توازن کو بگاڑ دیں۔ دنیا کے بارے میں احساسِ مسئولیت اور اس کی نگرانی و بہبود کی ذمہ داری کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، ہم مغرب میں اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے مادی اور روحانی پہلو میں جو توازن ہم کھو چکے ہیں وہ ہمیں دوبارہ حاصل کرنا ہے، یہ نہ ہوا تو ہم تباہی تک پہنچ جائیں گے۔
آج ہم رسل و رسائل و ابلاغ کی ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس کا تصور بھی ہمارے آباؤ اجداد نہ کر سکتے تھے۔ عالمی معیشت باہم منحصر ایک وحدت کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ معاشرہ کے مسائل، زندگی کا معیار، ماحول، یہ سب اپنے اسباب و نتائج کے حوالہ سے عالمی نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم میں کوئی صرف خود انہیں حل نہیں کر سکتا۔
اسلامی اور مغربی دنیا کو مشترک مسائل کا سامنا ہے۔ ہم اپنے معاشروں میں آنے والی تبدیلیوں سے کس طرح اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہیں؟ ہم ان نوجوانوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو معاشرہ کی اقدار اور والدین سے دور ہونے کا احساس رکھتے ہیں؟ ہم منشیات، ایڈز اور خاندانی نظام کے بکھر جانے کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں؟ ہمارے اندرون شہر کے مسائل قاہرہ اور دمشق کے مسائل کی طرح نہیں ہیں لیکن انسانی تجربات میں مماثلت ضرور ہے۔ منشیات کا بین الاقوامی کاروبار، اور ماحول کو ہم جو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے مشترک مسائل ہیں۔ جس طرح بھی ہو، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہو گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو درست تعلیم دینا ہو گی تاکہ ان کا نقطۂ نظر اور سوچ ہم سے مختلف ہو اور وہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ مشترک مسائل کے حل کے سلسلہ میں اسلامی اور مغربی دنیا ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔
ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ مناسب، کہ ماضی کی سیاست اور علاقائی تلخیوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ ہمیں اپنے تجربات میں ایک دوسرے کو شریک کرنا ہو گا۔ باہم تبادلہ خیال کرنا ہو گا۔ ثقافتی ورثہ میں جو کچھ مشترک ہے اسے اپنانا ہو گا۔ ہمیں تدبر کی اہمیت کو محسوس کرنا ہو گا تاکہ ہمارے ذہن کشادہ ہوں اور دلوں کے قفل بھی کھلیں۔ یقیناً عالم اسلام اور مغرب ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں چاہیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہیں، ضروری نہیں کہ ان میں تصادم ہو، اسلام اور مغرب ایک دوسرے کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ ہم دونوں کو مل کر بہت کچھ کرنا ہے۔ باہمی نفرت کو ختم کرنے اور خوف و بد اعتمادی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کیا جانا ہے۔ ہم اس راہ پر جتنا آگے بڑھیں گے آنے والی نسلوں کے لیے اتنی ہی بہتر دنیا بنا سکیں گے۔
پاکستان کے بارے میں امریکی عزائم کی ایک جھلک
وزیر اعظم پاکستان کے نام کھلا خط
ڈاکٹر محمود الرحمٰن فیصل
السلام علیکم!
اتفاق سے آپ کی دوسری وزارتِ عظمٰی سیاستِ دوراں میں کچھ تیزی لانے کا باعث بنی ہے۔ یہ حکومت بنانے میں کامیابی کا شاخسانہ ہے کہ آپ نے انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور شفاف قرار دیا ہے۔ اس سبب سے جہاں الیکشن کمیشن، فوج اور عدلیہ شکریہ کے مستحق قرار پائے ہیں وہاں سب سے زیادہ خراجِ تحسین نگران وزیر اعظم معین قریشی کو ملنا چاہیے جو آپ سے وزارتِ عظمٰی کے بدلہ میں پھولوں کا گلدستہ وصول کر کے سیدھے واشنگٹن واپس پہنچے، وہ اس مشن کی تکمیل کامیابی سے کر چکے تھے جسے پورا کرنے کے لیے انہیں درآمد کیا گیا تھا۔
قبل ازیں پاکستان کو امریکی نوآبادیاتی نظام (Neo-colonialism) کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور امریکی سفیر کو یہاں وائسرائے بہادر کا درجہ حاصل تھا۔ لیکن اب بات اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے اور انکل سام اپنے احکامات پر حرف بحرف عملدرآمد کرانے پر بضد ہے۔ نگران حکومت نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ریکوری ٹیم کا کردار ادا کیا۔ معین قریشی نے ایک تحلیل کنندہ (Liquidator) کی طرح پاکستان کی عوام کا خون نچوڑ کر سود کی رقم بدیشی آقاؤں کی خدمت میں پیش کر دی۔ امریکہ جن اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران، لیبیا، عراق اور سوڈان کو نیچا دکھا کر عالمِ اسلام کو کمزور کرنے کا سلسلہ شروع کر چکا تھا، پاکستانی کرنسی کی قیمت کم کر کے وہی مقاصد حاصل کر لیے گئے۔ بنیادی ضروریاتِ زندگی کو مہنگائی کے ذریعے عام آدمی کی دسترس سے دور کر دیا گیا۔ پاکستانی باشندوں کو مقدمہ چلانے کے لیے امریکہ کے حوالے کر کے ملک کی عزت و ناموس کو نیلام کیا گیا۔ منشیات کے نام پر موت کی سزا کا آرڈیننس جاری کر کے ثابت کیا گیا کہ جو سزا امریکی شہریوں کو نہیں دی جا سکتی وہ پاکستان میں اس لیے نافذ کی گئی کہ یہ غلاموں کا ملک ہے، امریکی جنرل ہوور کو سیاچن جیسے علاقے کا دورہ کرایا گیا۔
نام نہاد عالمی مبصرین کی ٹیمیں بھی ایک سازش کے تحت پاکستان آئی تھیں۔ امریکی قانون ساز ادارے نے ۱۹۹۰ء سے ’’پاکستان کی امداد‘‘ کے ممبران سے یہ شرط عائد کر رکھی ہے کہ پاکستان کی اقتصادی امداد، فوجی امداد اور تعلیم و تربیت کے پروگرام اس شرط پر جاری رکھے جائیں گے کہ پاکستان میں انتخابات عالمی نگرانی میں (Internationally Monitored) منعقد ہوں گے اور خصوصی عدالتیں ان کی راہ میں مزاحمت نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ٹیموں سے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے گئے۔ یہ ملکی معاملات میں بیرونی مداخلت کی بہترین مثال تھی۔ صہیونی لابی کی اس سے بھی بڑی سازش پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم (Roll back) کرنا ہے۔ عالمی نظامِ نو (نیو ورلڈ آرڈر) کی کامیابی کے لیے بھارت اور اسرائیل کے تعاون سے اس فریضہ کو سرانجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
فحاشی اور عریانی کا فروغ اخلاق باختہ مغرب کی اندھادھند پیروی سے ہو رہا ہے۔ یہودی گماشتے عیسائی دنیا کو فحاشی کا دلدادہ بنا کر اب باقی ماندہ اقوام کو بھی اسی دلدل میں گھسیٹ رہے ہیں تاکہ انہیں ناکارہ بنا کر اپنے دامِ پُرفریب میں لا سکیں اور اپنے نئے عالمی نظام کو دنیا پر مسلط کر سکیں۔ اگر اس کے حل کی طرف فوری توجہ نہ دی گئی تو ایڈز کی وبا مسلم ممالک کا رخ کرے گی۔
نفاذِ شریعت (Islamaization) سے دراصل اسلام کی نشاۃِ ثانیہ اور اس کا احیا مراد ہے۔ درباری ملاؤں کی تخمین و ظن سے دامن بچاتے ہوئے اسلام کے ازلی، ابدی اور آفاقی اصولوں پر مبنی نظام کا قیام ضروری ہے۔ آپ کی سابقہ کابینہ کے ایک اجلاس میں شرعی قوانین کو فرسودہ (Archaic) اور وحشیانہ (Barbaric) کہا گیا تھا جس کا نوٹس سپریم کورٹ نے بھی لیا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آئندہ مغربی پراپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر سابقہ روش کو خیرباد کہا جائے۔
آئین میں چند اسلامی دفعات نمائشی طور پر شامل کر دی گئی ہیں لیکن انہیں دیگر دفعات پر کوئی فوقیت نہیں دی گئی۔ وزارتِ قانون پر غیر اسلامی قوانین بنانے پر کوئی قدغن نہیں۔ یہ عوام پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اگر فارغ ہوں تو اپنے وسائل خرچ کر کے ان غیر اسلامی قوانین کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر عدالت انہیں غیر اسلامی قرار دے بھی دے تو حکومت حسبِ عادت سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیتی ہے۔ سالہا سال کے بعد اگر فیصلہ ہو جائے تو سرکار کارپرداز معمولی ردوبدل کے بعد وہی قانون دوبارہ نافذ کر دیتے ہیں اور معترضین کو ایک بار پھر وفاقی شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
پارلیمنٹ کے اکثر ممبران بنیادی اسلامی تعلیمات سے نابلد ہوتے ہیں اور آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ کے تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے بھی پارلیمان میں جا بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا قوانین وہ نہیں بناتے، بلکہ وزارتِ قانون میں بیٹھا ہوا ایک ڈرافٹس مین تیار کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کا کام صرف ان پر انگوٹھا لگانا ہوتا ہے۔ اتنے اہم معاملہ سے حکومت کا اغماض، غفلت شعاری کے زمرہ میں آتا ہے اور اس غیر ذمہ داری پر اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔
سب سے بڑی مثال سود کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، جس پر عملدرآمد کرنے کی بجائے سابقہ حکومت اپیل میں چلی گئی۔ یہ فیصلہ راقم الحروف کی درخواست پر دیا گیا اور اب اس کی اپیل ’’وفاق پاکستان بنام ڈاکٹر محمود الرحمٰن فیصل‘‘ سپریم کورٹ میں سماعت کی منتظر ہے۔ سود کے خاتمہ کے لیے آئین میں موجود دفعات پر کاربند ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تمام علماء، عامۃ الناس، دینی و سیاسی جماعتوں کے متفقہ مطالبہ کے باوجود اس فیصلہ کو من و عن تسلیم نہیں کیا گیا اور نہ سپریم کورٹ سے یہ اپیل واپس لی گئی۔ یہ سود کا وبال تھا جو سابقہ حکومت کی کشتی ڈبو گیا، اب گیند آپ کی کورٹ میں ہے، اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکم کو پسِ پشت ڈالنا کسی طرح بھی آپ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں قرآن کی سرزنش ملاحظہ ہو:
’’اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو باقی ماندہ سود کو ختم کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔‘‘ (البقرہ ۲۷۸ و ۲۷۹)
سود کی ممانعت صرف دینِ اسلام میں ہی نہیں بلکہ دیگر آسمانی ادیان بشمول عیسائیت و یہودیت میں بھی سود کا لین دین منع ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جدید ماہرینِ معاشیات سود کے ظالمانہ نظام کی تباہ کاریوں سے واقف ہو چکے ہیں، اسی لیے لارڈ کینز نے دورِ حاضر میں صفر شرح سود (Zero Rate of Interest) کو مثالی قرار دیا ہے اور اس طرح سود کے خاتمہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ دنیا بھر میں پائی جانے والی غربت، مہنگائی، افراطِ زر اور معاشی ناہمواری سود کی مرہون منت ہے۔ ہر سال کی جانے والی خسارے کی سرمایہ کاری اور انڈیکیشن سود کی مرہون منت ہے۔ اس کا خاتمہ ہو جائے تو پوری دنیا سکھ کا سانس لے گی۔ اگر عالمی مالیاتی نظام مختلف ہے تو ہم اس کے پابند نہیں۔ ابتدا میں قربانی بھی دینا پڑے تو ایک نظریاتی مملکت ہونے کی بنا پر پاکستان کو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔
کشمیر کا مسئلہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ آپ کے انتخاب پر سب سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نرسیماراؤ نے مبارکباد بھجواتے ہوئے کشمیر کے بارے میں مذاکرات کی پیشکش کی۔ بھارتی حکمران آپ کی حکومت سے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ماضی کا تجربہ ان کے سامنے ہے۔ بھارت نے اپنی بڑی کامیابی شملہ معاہدہ کی صورت میں پہلے ہی حاصل کر رکھی ہے، جس کی رو سے کشمیر کا مسئلہ کے حل کے لیے عالمی ادارے بشمول اقوامِ متحدہ مداخلت کے لیے مجاز نہیں ہیں۔
پاک فوج کا تشخص بہتر بنانے اور امیج بحال کرنے کی جانب کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ۱۹۷۱ء کے بعد آرمی کا مورال بلند کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور اسے مستقل سیاسی کردار دیے جانے کی بات ہوئی۔ فوج کے ایک سربراہ کو آپ نے تمغۂ جمہوریت بھی دیا۔ آپ کی پارٹی کے پہلے دورِ حکومت میں سول مارشل لاء کی بدعت ڈالی گئی جس کے اثرات آمرانہ سول حکومت کی صورت میں سامنے آئے۔ جمہوریت ہنوز اس قابل نہیں ہو سکی کہ فوج کی مدد کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔
خلیج کی جنگ کے تلخ تجربہ کے بعد اسلامی، آئینی اور اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر پاک فوج کو ایک مرتبہ پھر امریکی کمان میں صومالیہ میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ امریکی صہیونی شاطروں نے صومالیہ میں پاک فوج کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسے بدنام کیا، اور اپنے عالمی نظام کی توسیع اور سوڈان سمیت افریقہ کے مسلم ممالک میں اسلامی احیا کی تحریک کو روکنے کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ تقریباً سو فیصد مسلم آبادی والے ملک صومالیہ میں قحط زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں کو پسِ پشت ڈال کر وہاں کے سیاسی نظام میں مداخلت اور عوام کے قتلِ عام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ خود امریکہ میں صومالیہ سے فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ زور پکڑنے کے باوجود ہمارے اربابِ اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ صومالیہ میں امریکی مداخلت کے عزائم مندرجہ ذیل تھے جو اس نے بڑی حد تک حاصل کر لیے ہیں:
(۱) اسلامی ملک صومالیہ کے حصے بخرے کرنا، (۲) بحیرہ احمر اور بحر ہند میں آبی راستوں کا کنٹرول حاصل کرنا، (۳) صومالیہ میں خام لوہے اور یورانیم کے ذخائر پر قبضہ کرنا، (۴) سوڈان میں مداخلت کے لیے راہ ہموار کرنا، (۵) بھارت کو اسرائیل کے اتحادی کی حیثیت سے صومالیہ کے معاملات میں لانا، (۶) پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور پاک فوج کو نقصان پہنچانا، (۷) دنیا بھر میں آئندہ فوجی مداخلت کے لیے جواز فراہم کرنا، (۸) عیسائی قوتوں اور حلیف مسلمانوں کو صومالیہ کی اسلامی ریاست تباہ کرنے کے لیے استعمال کرنا، (۹) صومالیہ کا تشخص اور اسلامی نظریہ تباہ کرنا، (۱۰) بڑی تعداد میں صومالی باشندوں کا انخلا اور ہجرت، (۱۱) اور عالمی اسلامی تحریک کو نقصان پہنچانا۔
ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی اہم ذمہ دری یہ ہے کہ آئندہ کسی بھی فوجی مہم میں پاک فوج کو سوچے سمجھے بغیر ملوث نہ کیا جائے تاکہ اس کی کردارکشی کی نوبت نہ آئے۔ بوسنیا کے حالات اس امر کے زیادہ متقاضی تھے کہ افواج وہاں بھجوائی جاتیں۔
فلسطین کے حالیہ واقعات انتہائی تشویش کا باعث ہیں۔ یاسر عرفات کا اسرائیل سے معاہدہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک بزدلانہ اقدام ہے۔ یہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین کو فروخت کر دینے کے مترادف ہے۔ یہ معاہدہ کم اور اعلامیہ زیادہ ہے۔ اسرائیل کی شروع سے کوشش تھی کہ اسے اپنے وجود کا جواز مل جائے۔ محدود پیمانے پر بلدیاتی اختیارات کے حصول کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے اہلِ فلسطین کبھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسلامی ممالک کو یہ معاہدہ ہرگز تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان، جس نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے لیے سفیر کا تقرر بھی کر دیا تاکہ اسرائیلی حدود میں سفارتخانہ کھولا جا سکے، امریکی دباؤ کا مظہر ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھنا پاکستانی حکمرانوں کے لیے ناممکن ہو گا کیونکہ ایسا کرنا نظریۂ پاکستان کی نفی، قبلۂ اول سے غداری اور عالمِ اسلام پر یہودی تسلط کے مترادف ہے۔
پاکستانی سیاست میں وراثت اور تجارت کے داخلہ سے نظامِ حکومت جمود کا شکار ہے۔ سیاستدان اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور تجارت کرنے کے نظریہ سے سیاست میں آئے ہیں۔ وراثت کا عنصر اس قدر مضبوط ہے کہ اگر آپ بھٹو کی بیٹی نہ ہوتیں تو کبھی پاکستان کی وزیراعظم نہ بن سکتیں۔ یہاں لوگوں کی قدر و منزلت ان کی اہلیت کی بنا پر نہیں کی جاتی۔ نااہلی کا یہ حال ہے کہ صدر سے لے کر چپڑاسی تک کوئی بھی اپنی اہلیت یا میرٹ کی بنا پر اپنے عہدے تک نہیں پہنچا۔ ہمارے ہاں پائی جانے والی جمہوریت کا مغربی ایڈیشن بڑے پیمانے پر اصلاح طلب ہے۔ اگرچہ آپ دخترِ مشرق کہلاتی ہیں لیکن آپ کی تعلیم و تربیت آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسے سکہ بند مغربی اداروں میں ہوئی ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک کا یہ سب سے عظیم المیہ ہے کہ یہاں مغرب کی حکومت ہے۔
یہاں کی سیاست میں لوٹے، لفافے، ڈبے اور بریف کیس بھی شامل ہو چکے ہیں۔ آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ جمہوری نظام بجائے خود آخری منزل نہیں بلکہ حصولِ مقصد کی طرف ایک قدم ہے۔ الیکشن ۱۹۹۳ء میں ۶۵ فیصد عوام نے ووٹ نہ ڈال کر اس نظام سے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے۔ چند فیصد ووٹ حاصل کرنے والے خود فیصلہ کریں کہ وہ جمہوری اصول کی بنیاد پر سو فیصد عوام کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں اور کس مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں۔ اکثریت کی حکومت کا اصول غلط ثابت ہو چکا ہے۔ نیز یہ انتخابات کسی قومی معاملہ (Issue) کی بجائے شخصیات کی بنیاد پر منعقد ہوئے۔ لہٰذا یہ ثابت کرنا کہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کوئی ایشو نہیں، انصاف پر مبنی نہیں۔ ان انتخابات میں اسلامی جماعتوں کا حصہ لینا مناسب نہیں تھا۔ بعض اسلام پسندوں نے تیر بے ہدف (Misguided Missile) کا کام کیا لہٰذا الیکشن کا نتیجہ ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اسمبلیوں میں ہندسوں کا کھیل (Game of Numbers) شروع ہوا، کوئی بھی پارٹی تنِ تنہا حکومت بنانے کے قابل نہیں تھی۔ بات پھر وہیں ہارس ٹریڈنگ تک جا پہنچی۔ لہٰذا سپورٹس مین سپرٹ، اپوزیشن کو جائز مقام دینے، مخالفت برائے مخالفت نہ کرنے، اقتدار کی میوزیکل چیئر کا کھیل جاری نہ رکھنے، اکھاڑ پچھاڑ نہ کرنے کی بات اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔
موجودہ نظامِ انتخابات اور اس میں ہونے والے اسراف و تبذیر کے شیطانی عمل کو وفاقی شرعی عدالت غیر اسلامی قرار دے چکی ہے۔ لیکن حکومت حسبِ عادت اپیل میں چلی گئی اور اب تک اس فرسودہ نظام کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود ہیں۔ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے مناسب قانون سازی نہیں کی گئی۔ امیدوار کی تعلیمی اہلیت اور دیانتداری کا اعلیٰ معیار نہیں پرکھا جاتا۔ ووٹر کی صرف عمر کی حد مقرر کرنے کی بجائے اس کی ذہنی استعداد اور اخلاقی حالت کو جانچنا ضروری ہے۔ امیدوار کے علاوہ ووٹر کا معیار بھی مقرر کیا جائے۔ مزراعت، برادری اور سرداری نظام کے اثرات کو ختم کیا جائے۔ دھن، دھونس اور دھاندلی کے امکانات کا سدباب کیا جائے۔ انتخابی اخراجات امیدوار کے ذمہ نہ ہوں بلکہ اس کا تعارف ذرائع ابلاغ کے ذریعے الیکشن کمیشن کے زیرانتظام کرایا جائے۔ دور رس انتخابی اصلاحات کے بغیر موجودہ نظام جمہوری کہلانے کا مستحق نہیں۔ سیاسی نظام ہی نہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی میدانوں میں بھی اسلامی بنیادوں پر انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔
عارضی حدبندیوں کے ٹوٹنے اور نوعِ انسانیت کے قریب آجانے کی بنا پر آپ نے جس عالمی گاؤں (Global Village) اور نئے عالمی نظام کا ذکر کیا ہے وہ ظالمانہ صہیونی نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ تیسری دنیا کے عوام کو اس میں ایک ’’پینڈو‘‘ سے زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اقوامِ متحدہ کا روبہ زوال ادارہ بھی یہودی عزائم کی تکمیل کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی کو وہ اپنی عالمی حکومت (World Government) کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس ادارہ میں مسلمان ممالک کی اکثریت کے باوجود انہیں ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے۔ انسانی بنیادی حقوق کے اپنے ہی چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے متعدد ممالک پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جن کے نقصان دہ اور مہلک اثرات بے گناہ عوام کو برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اس تناظر میں دنیا بھر کی مظلوم اقوام خصوصاً اسلامی ممالک کو اپنے لیے علیحدہ لائحہ عمل اور اپنے الگ عالمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرہ ارض کی یہ عظیم بستی واقعی انسانوں کے بسنے کے قابل بن سکے۔ اس ضمن میں پاکستان کیا کردار ادا کرتا ہے، اس کا انتظار ہے۔
آخر میں، میں آپ کے اس عندیہ کی جانب آتا ہوں جس میں امریکہ سے تعلقات کی بحالی کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ امریکی حکمرانوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی اسلامی ملک سے ہمدردانہ رویہ رکھیں گے، قطعاً عبث ہے۔ روس کے زوال کے بعد اب دنیا یکطرفہ ہو کر طاقت کا توازن کھو چکی ہے، طاقت کا یہ توازن اسلامی دنیا اپنے اتحاد کے ذریعے قائم کر سکتی ہے بشرطیکہ اس مقصد کے حصول کے لیے خلوص دل سے کام کیا جائے۔
والسلام، ڈاکٹر محمود الرحمٰن فیصل
(بشکریہ، ماہنامہ محقق لاہور ۔ دسمبر ۱۹۹۳ء)
اکیسویں صدی اور اسلام ۔ مغرب کیا سوچتا ہے؟
محمد عادل فاروقی
۲۱ ویں صدی کی اصل سپرپاور مسجد ہے یا گرجا؟ بلاشبہ یہ وہ نئی سرد جنگ ہے جو اب بھرپور انداز میں مشرق اور مغرب کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ اس جنگ کے اصل حریف مسلمان اور عیسائی ہیں۔ مغربی مفکر جان آسپوزیٹو نے اپنی نئی ریسرچ میں اسلام اور عیسائیت کی نئی محاذ آرائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تقریباً تقریباً وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں جو آج سے ۷۵ سال پہلے سلطنتِ عثمانیہ کے زوال کے وقت تھے۔ جس طرح سلطنتِ عثمانیہ کمزور ہوئی تھی اس طرح آج کلیسا پر زوال کے گہرے سائے پڑ چکے ہیں۔ جان کا کہنا ہے کہ جس طرح اس زمانے میں مسلمانوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان کا سورج ڈوبنے والا ہے، اس طرح آج عیسائی دنیا کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ان کی پے در پے غلطیوں کے باعث عیسائی متعدد اداروں کو زوال آ رہا ہے۔
جان کی تحقیق کا مقصد عیسائیوں کو بتانا ہے کہ خلیجی جنگ اور اس علاقے کے اختلافات نے دراصل مسلمانوں کو اسی انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے جس طرح صلیبی جنگوں کے وقت عیسائی سوچ رہے تھے۔ جان کا کہنا ہے کہ اب مسلمانوں کو بے وقوف خیال کرنا عیسائیت کی سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ اگر مسلمان ناسمجھ یا نادان ہوتے تو وہ ایٹم بنانے کی کوشش نہ کرتے۔ پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے عرب اور اسلامی ممالک مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اسلامی بم بنانے کے بارے میں عملی طور پر غور نہ کرتے۔ آج اگر پاکستان، عراق اور ایران نے ایٹمی میدانوں میں صلاحیتیں حاصل کی ہیں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ عیسائی ممالک ان ملکوں کو پسماندہ ہی خیال کرتے رہے، حالانکہ ان ملکوں کے حالات خراب ضرور ہیں لیکن ان کے افراد دماغ اور ذہانت کے لحاظ سے پسماندہ نہیں۔
’’اسلامک تھرٹ‘‘ کے مصنف نادر جوزف نے کہا کہ آج کلیسا کے زوال کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عیسائیت کا پرچار اسلامی تبلیغ کے مقابلے میں انسانوں کو مطمئن کرنے کے فائنل راؤنڈ میں جا چکا ہے۔
ویٹی کن پادریوں کا کہنا ہے کہ آج ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم مسلم مبلغ احمد دیدات کے مقابلے میں کوئی مستند پادری نہیں لا سکے جو لوگوں کو مذہب کے بارے میں اس طرح مطمئن کرے جس طرح احمد دیدات کرتا ہے۔ پادری البرٹ کا کہنا ہے کہ عیسائیت کا اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہو گا کہ جہاں احمد دیدات عیسائیوں سے مناظرہ کرنے آتا ہے وہاں پادریوں کی شکست کے بعد پیدائشی عیسائیوں کی اکثریت اسلام قبول کر لیتی ہے۔ پادری البرٹ نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی حکومتوں نے خود نوٹس نہ لیا تو امریکہ سمیت مغرب کے تمام بڑے بڑے ملکوں کے کٹر عیسائی باشندے، جو مغرب کی اصل طاقت ہیں، پادریوں کی نالائقی کے باعث دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔
لندن کے معروف پادری فادر ملٹن کا کہنا ہے کہ روسی بٹوارے کے بعد امریکہ کے ورلڈ اسٹیج پر اکیلا رہ جانے سے مسلمان ’’دنیا‘‘ پر ہولڈ کرنے کی پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں۔ فادر ملٹن نے واشنگٹن میں عیسائیوں کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ اور امریکہ پر تنقید کی کہ وہ سیکولر بننے کے چکر میں مسلمانوں کے مفادات پورے کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی امداد اور اداروں کی خدمات عیسائیت والے ملکوں کو دینے کی بجائے اسلامی ملکوں کو دے رہے ہیں۔ فادر ملٹن نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان، ایران اور سعودی عرب کو دفاع کے لحاظ سے تکنیکی امداد نہ دیتا تو آج یہ ملک مغرب کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں نہ آتے۔ فادر ملٹن نے تو اسلامی بم بننے کا ذمہ دار بھی امریکہ اور دوسری مغربی سپر طاقتوں کو قرار دیا ہے۔
ایک برطانوی ریٹائرڈ جرنیل نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، ایک بین الاقوامی میگزین میں مسلم اور عیسائی طاقت کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستانی، اردنی، مصری اور ۔۔۔۔۔۔۔ برطانیہ نے ترتیب دے کر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماری ہے۔ جرنیل نے لکھا ہے کہ لوگ جب اپنی افواج کی مقتدر حیثیت میں آتے تو ان ملکوں کی بنیاد پرست حکومتوں کے اشارے پر یہ امریکہ اور برطانیہ کے سکھائے ہوئے طریقوں سے ہی انہیں ’’خرچ‘‘ کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کو محسوس نہیں کریں گے۔ جرنیل نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ اسلامی دنیا میں جہاد، شہادت اور غازی کا جذبہ ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ آسانی سے صلیبی نشان رکھنے والے نہیں کر سکتے۔ جرنیل نے اپنے مشاہدے کے تجربات لکھتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے فوجیوں کو میدانِ جنگ یا فوجی نوعیت کے مقامات پر ڈیوٹی کے دوران مرنے کا شوق ہے اس طرح کا شوق عیسائی فوجیوں میں نہیں۔ عیسائی فوجی صرف ہتھیار اور صلاحیت پر یقین رکھتے ہیں جبکہ اسلامی فوجی جذبات کو ہتھیار اور صلاحیت پر فوقیت دیتے ہیں اور یہ چیز جنگوں میں فتح دلاتی ہے۔
غیر ملکی جریدے رائزے ویسٹ نے اپنے مارچ کے شمارے میں ایک پورا ایڈیشن اسلامی گوسٹ ’’اسلامی بھوت‘‘ کے نام سے شائع کیا ہے جس کا نچوڑ یہ ہے کہ اس صدی میں مغرب والوں کو ہتھیار بنانے، اسلحہ بڑھانے، ایٹم بم مارنے یا عالمی سیاست کرنے کی بجائے مسلمانوں کی ایٹمی طاقت کو فورًا دبانے کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کرنے چاہئیں۔
جریدے یو ایس نیوز نے اپنے ایک حالیہ شمارے میں عیسائیت کو خبردار کرتے ہوئے اپنے اداریے اور مضامین میں کہا ہے کہ پاکستان، ایران، عراق، مصر، اردن اور عرب ممالک کی آج کی فوجی طاقت کسی وقت بھی اچانک بپھر کر سارے یورپ میں عیسائیت کے پچھلے اقتدار کا فیوز اڑا سکتی ہے۔
غیر ملکی اخبارات میں عیسائی مشنریوں کے شائع ہونے والے تبلیغی اشتہاروں سے حاصل ہونے والے مواد میں صاف صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں پڑی پھوٹ کو ختم کرنے کی بجائے عیسائیوں کو خود کو متحد اور مضبوط کرنا ہو گا ورنہ اسلام کے جنونی کچھ عرصہ بعد دنیا میں اپنا اقتدار قائم کر لیں گے۔
دی ڈیلی انڈیپینڈینٹ نے اپنے مارچ کے ایک روزنامے میں مسلم عیسائی طاقت کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند برسوں میں جو عالمی سطح پر تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر مسلمانوں کے فائدے میں جا رہی ہیں۔ اس نے عیسائی لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اب نظرانداز کرنے کا انداز چھوڑ دیں اور مسلمانوں کی اصل ترقی کے محرکات کے بارے میں غور کریں اور دیکھیں آج کل مسلمان پھر سے کیسے سر اٹھا رہے ہیں۔
سی آئی اے نے بھی اپنی حالیہ رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ امریکی مفادات کو سب سے بڑا خطرہ اسلامی بنیاد پرستی سے ہے۔ سی آئی اے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب صدام اتنا خطرناک نہیں رہا جتنا خطرناک مجاہدین کی تحریکوں میں حصہ لینے والے مسلمان ہیں۔
ایک اور اہم مغربی مفکر جان لیفن نے اپنی تحقیقی کتاب ’’دی ڈینجر آف اسلام‘‘ کے بعد انکشاف کیا ہے کہ مغربی دانشور مسلمانوں کی موجودہ سیاسی اور مذہبی قیادت کو نہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ لیفن نے کہا کہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ لیبیا، سعودی عرب، ایران اور پاکستان اس وقت اسلامی بنیاد پرستوں کی نمائندگی کر رہے ہیں کیونکہ کشمیر، افغانستان، بوسنیا اور جہاں جہاں بھی مسلمان آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان ملکوں کے باشندے ہی زیادہ تر وہاں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔۔۔ سپوزیٹو کے حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ مسلمان ممالک اور اسلامی تحریکیں اب دقیانوسی طور طریقے چھوڑ کر جدید انداز میں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسلامی تحریکیں مذہبی نعروں کی بجائے جمہوری، معاشی اور سیاسی سہولتوں کا فائدہ دے کر اپنے لوگوں کو اسلام کے پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مغرب میں سیکولرازم کا زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے جبکہ عملی طور پر سیکولرازم اسلامی ممالک اختیار کر رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے اسلامی ملکوں کی غیر مسلم اقلیتیں بھی عیسائیت سے آخری جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گی۔۔۔۔ سپوزیٹو کا کہنا ہے کہ اسلام کی کامیابی صرف اور صرف ایک نکتہ میں ہے کہ اسلام میں عیسائیت کے مقابلے میں موجودہ حالات و واقعات کے مطابق خود کو تبدیل اور جدید رجحان اپنانے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ شاید اسی وجہ سے آئندہ صدی میں عیسائیت اسلام سے مات کھا جائے گا۔
ویسٹ ورلڈ نامی جریدے نے لکھا ہے کہ دراصل صدر بش نے خلیجی جنگ میں اپنی تھانیداری دکھا کر درحقیقت گرجے کو کمزور اور مسجد کو مضبوط کیا ہے۔ وہ امریکی فوج جس کے بارے میں ساری اسلامی دنیا ڈرتی رہتی تھی، اس کو اسلامی دنیا کے فوجیوں میں مکس کر کے اسلامی فوجیوں کو بتا دیا کہ امریکی فوج اصل میں کتنے پانی میں ہے اور آئندہ کبھی جنگ ہوئی تو اس فوج کو کیسے شکست دینی ہے۔ ویسٹ ورلڈ نے کہا کہ صدر کلنٹن بھی بش کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔
مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشی صورتحال کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے ’’اکنامک‘‘ غیر ملکی جریدے نے لکھا ہے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران مسلم اور عرب ممالک نے مغرب کی پالیسیوں کو اختیار کر کے اپنی دولت کے استعمال سے مکمل آگاہی حاصل کر لی ہے، جو اب آئندہ سالوں میں مغرب کو اقتصادی موت دینے کے مترادف ہو گا۔
مغربی تاریخ دان مائیکل ہورن ہائے کا کہنا ہے کہ اب فطرت اور قدرتی طور پر بننے والے حالات و واقعات، وہ تمام علاقے جو عیسائی دنیا نے فراڈ سے اسلامی دنیا سے چھین لیے تھے، لوٹا رہی ہے۔ اس کی مثال اس نے وسطی ایشیائی ریاستوں سے دی۔ افغانستان، بوسنیا اور وسطی ایشیائی ریاستوں میں جیسے جیسے اسلامی بنیاد پرست مستحکم ہوتے گئے ویسے ویسے وہ عیسائی دنیا کو اپنے نرغے میں لیتے جائیں گے۔ مائیکل نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے موجودہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اب عیسائیوں میں وہ تمام قباحتیں آ چکی ہیں جو مسلمانوں کے دنیائے عالم سے اقتدار مٹانے کا سبب بنی تھیں۔
تقریباً تمام غیر ملکی جرائد گزشتہ چھ ماہ سے اپنے اداریوں اور مضامین میں یہ دہائی دینے لگ پڑے ہیں کہ کلیسا اور حکومتی ایوانوں میں عورتوں کو مقتدر حیثیت دے کر عیسائیوں نے گرجے کی بنیادی خود کھوکھلی کر دی ہیں۔
’’دی رائزنگ ہیرلڈ‘‘ نے اپنے فروری کے ایشو میں لکھا ہے کہ اسلامی ممالک کو ان کے ایٹمی پروگراموں سے باز نہ رکھنے میں ناکامی نے جنگ سے پہلے ہی مغرب کو شکست اور مشرق کو فتح دلائی ہے۔ رائزنگ نے مسلم دنیا کو اوپر اٹھانے کا کریڈٹ شاہ فیصل مرحوم، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، شہنشاہ ایران، صدر اسحاق، امام خمینی، کرنل قذافی، صدام حسین اور ڈاکٹر قدیر کو دیا ہے اور ان کی تصاویر بھی شائع کی ہیں۔
(بشکریہ ’’جنگ‘‘ لندن ۔ ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۳ء)
شہیدانِ بالاکوٹ
حضرت شاہ نفیس الحسینی
قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر
وہ پہنچے بارگاہِ حق میں کتنے سرخروہو کر
فرشتے آسماں سے ان کے استقبال کو اترے
چلے ان کے جلو میں با ادب، با آبرو ہو کر
جہانِ رنگ و بو سے ماورا ہے منزلِ جاناں
وہ گزرے اس جہاں سے بے نیازِ رنگ و بو ہو کر
جہادِ فی سبیل اللہ نصب العین تھا ان کا
شہادت کو ترستے تھے سراپا آرزو ہو کر
وہ رُہباں شب کو ہوتے تھے تو فُرساں دن میں رہتے تھے
صحابہؓ کے چلے نقشِ قدم پر ہو بہو ہو کر
مجاہد سر کٹانے کے لیے بے چین رہتا ہے
کہ سراَفراز ہوتا ہے وہ خنجر در گلُو ہو کر
سرِ میداں بھی استبالِ قبلہ وہ نہیں بھولے
کیا جامِ شہادت نوش انہوں نے قبلہ رو ہو کر
زمین و آسماں ایسے ہی جانبازوں پہ روتے ہیں
سحابِ غم برستا ہے شہیدوں کا لہو ہو کر
شہیدوں کے لہو سے ارضِ بالاکوٹ مُشکِیں ہے
نسیمِ صبح آتی ہے اُدھر سے مُشکبو ہو کر
نفیس ان عاشقانِ پاک طینت کی حیات و موت
رہے گی نقشِ دہر اسلامیوں کی آبرو ہو کر
امریکی عزائم: ورلڈ اسلامک فورم کے زیر اہتمام پہلا علماء کنونشن
ادارہ
عالمِ اسلام کے بارے میں امریکہ کے عزائم اور پاکستان کے داخلی معاملات میں بڑھتی ہوئی امریکی مداخلت کے خلاف ورلڈ اسلامک فورم نے علمائے کرام کے اجتماعات کے سلسلہ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا علماء کنونشن ۲۶ دسمبر ۱۹۹۳ء کو مسجد باب الرحمت (پرانی نمائش، کراچی) میں مولانا فداء الرحمٰن درخواستی کی زیرصدارت منعقد ہوا جس میں کراچی کے مختلف حصوں سے علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدظلہ العالی، خطیب اسلام مولانا محمد اجمل خان، مولانا اللہ وسایا، مولانا نظام الدین شامزئی اور سید سلمان گیلانی نے خطاب کیا۔ جبکہ مولانا محمد انور فاروقی نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سرانجام دیے۔ کنونشن کا آغاز قاری مفتاح اللہ نے تلاوت کلامِ پاک سے کیا اور اس کے بعد ورلڈ اسلامک فورم کے چیئرمین مولانا زاہد الراشدی نے کنونشن کے اغراض و مقاصد پر مشتمل مندرجہ خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔
استقبالیہ کلمات
قابلِ صد احترام علمائے کرام، مشائخ عظام و راہنمایانِ ملت!
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ورلڈ اسلامک فورم کی طرف سے آپ سب بزرگوں کا شکرگزار ہوں کہ انتہائی مختصر نوٹس پر آپ حضرات اس اجتماع میں تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر سے نوازیں، آمین۔
حضراتِ محترم! آج کے اس علماء کنونشن کے دعوت نامہ سے آپ حضرات کو علم ہو چکا ہے کہ یہ اجتماع عالمِ اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاملات میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت اور اس کے روز افزوں منفی اثرات سے پیدا شدہ صورتحال کا خالصتاً دینی نقطۂ نظر سے جائزہ لینے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اکابر اہلِ علم علمائے حق کی تاریخی روایات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے اس نازک اور حساس مسئلہ پر شرعی اصولوں کی روشنی میں امتِ مسلمہ کی راہنمائی کریں تاکہ علماء اور دینی کارکن اس کی بنیاد پر اپنی آئندہ جدوجہد اور تگ و تاز کی راہیں متعین کر سکیں۔
راہنمایانِ قوم! علمائے حق کی تاریخ شاہد ہے کہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر جب بھی بیرونی قوتوں کی دخل اندازی اور سازشوں سے سابقہ پڑا ہے، علمائے امت نے آگے بڑھ کر ملتِ اسلامیہ کی راہنمائی کی ہے۔ تاتاری یورش کے خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی جدوجہد، اکبر بادشاہ کے دینِ الٰہی کے خلاف حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نعرۂ حق، مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی یلغار کے مقابلہ میں حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ کی مومنانہ تدبیریں، اور فرنگی استعمار کے تسلط کے خلاف حضرت شاہ عبد العزیز دہلویؒ کا فتوٰی جہاد علمائے حق کی اسی جدوجہد کے سنگ ہائے میل ہیں جو آج بھی اسلام کی بالادستی اور امتِ مسلمہ کی خودمختاری کی منزل کی طرف ہماری راہنمائی کرتے ہیں اور تاریخ کے اسی تسلسل کے ساتھ حال کا رشتہ جوڑنے کے لیے آپ حضرات کو اس کنونشن میں شرکت کی زحمت دی گئی ہے۔
زعمائے ملت! امریکہ جو اس وقت سب سے بڑی عالمی قوت اور اسلام کے خلاف کفر کی تمام قوتوں کا نقیب ہے، عالمِ اسلام میں دینی بیداری کی تحریکات کو سبوتاژ کرنے اور بے اثر بنانے کے لیے جو جتن کر رہا ہے وہ آپ جیسے اصحابِ دانش و فراست سے مخفی نہیں ہیں، اور اس کے یہ مقاصد اب کسی پر پوشیدہ نہیں رہے کہ
- عالمِ اسلام کے کسی ملک میں اسلامی نظریاتی حکومت قائم نہ ہونے پائے،
- کوئی مسلم ملک معاشی خود کفالت اور اقتصادی خودمختاری کی منزل حاصل نہ کر سکے،
- کوئی مسلم ملک ایٹمی توانائی سمیت دفاع کی کوئی جدید تکنیک مہیا نہ کر سکے،
- عالمِ اسلام کے اتحاد اور سیاسی یکجہتی کی کسی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار نہ ہونے دیا جائے۔
اس مقصد کے لیے نہ صرف دنیائے کفر کی تمام قوتیں بلکہ عالمِ اسلام کی سیکولر لابیاں اور لادین قوتیں بھی امریکہ کے ساتھ شریکِ کار ہیں۔
اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے داخلی معاملات میں امریکہ کی مداخلت بھی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ یہ مداخلت جو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی اب بڑھتے بڑھتے یہ کیفیت اختیار کر گئی ہے کہ پاکستان عملاً امریکہ کی نوآبادی بن کر رہ گیا ہے، اور اس کی قومی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں امریکہ کی رضامندی کے بغیر اعلٰی سطح کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ
- امریکہ نے پاکستان کی امداد کو ۱۹۸۷ء میں جن شرائط کے ساتھ مشروط کیا تھا، روزنامہ جنگ لاہور (۵ مئی ۱۹۸۷ء) میں شائع شدہ ایک رپورٹ کے مطابق ان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے اور اسلامی اصطلاحات کے استعمال سے روکنے کے اقدامات واپس لینے کے علاوہ اسلامی قوانین کو انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے ان کے نفاذ سے باز رہنے کی شرائط بھی شامل ہیں، جن پر امریکہ بدستور قائم ہے اور پورا کرانے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔
- ماہنامہ محقق لاہور (دسمبر ۱۹۹۳ء) کے انکشاف کے مطابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے آخری دور میں ’’شریعت آرڈیننس‘‘ جاری کیا تو امریکی حکومت نے اس قدر سخت باز پرس کی کہ حکومتِ پاکستان کو اس پر عملدرآمد نہ ہونے کی یقین دہانی کرانا پڑی اور امریکہ کو سرکاری طور پر مطلع کرنے کے علاوہ دنیا بھر کے پاکستانی سفارتخانوں کو بھی ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ ان حکومتوں کو اس سے آگاہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی سرکاری طور پر منظور کرائے جانے والے ’’شریعت بل‘‘ میں قرآن و سنت کی بالادستی سے حکومتی ڈھانچے اور سیاسی نظام کو مستثنٰی قرار دینے جانے پر اسلام آباد میں متعین امریکی سفیر نے کھلم کھلا جس طرح اطمینان کا اظہار کیا وہ اس سلسلہ میں امریکی پالیسیوں کے رخ کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔
- پاکستان کو ایٹمی توانائی کے حصول سے روکنے اور اپنے دفاع کے لیے خاطرخواہ انتظام کے شرعی اور جائز حق سے محروم کرنے کے لیے امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ بزرگوں کے سامنے ہے، اور پاکستان کو اقتصادی طور پر محتاج اور اپاہج بنائے رکھنے کی امریکی پالیسی روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔
- کشمیر کو تقسیم کر کے امریکی فوجی اڈہ بنانے کا منصوبہ منظرِ عام پر آ چکا ہے اور امریکہ نے ایک طے شدہ پالیسی کے تحت پاکستان کی فوج کو صومالیہ میں الجھا کر وہاں کی مسلم آبادی سے پاک فوج کو لڑانے اور افریقی مسلمانوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی راہ ہموار کی ہے اور اس کے اثرات بتدریج سامنے آ رہے ہیں۔
ان حالات میں آپ بزرگوں کو زحمت دی گئی ہے کہ اسلام کی بالادستی، عالمِ اسلام کے اتحاد، مسلمانوں کی خودمختاری، مذہبی آزادی اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے امتِ مسلمہ کی راہنمائی فرمائیں اور دینی جماعتوں، علماء اور کارکنوں کے لیے ایک ایسا واضح لائحہ عمل متعین فرمائیں جو امریکی استعمار کے تسلط سے عالمِ اسلام اور پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کی دینی بنیاد ثابت ہو۔
میں ایک بار پھر تشریف آوری پر آپ سب بزرگوں کا شکرگزار ہوں، فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔
مولانا مفتی نظام الدین شامزئی
اس کے بعد جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے استاذ الحدیث مولانا مفتی نظام الدین شامزئی نے خطاب کیا اور عالمِ اسلام کے حوالہ سے امریکی عزائم کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ عوام اور دینی حلقوں کو اس سلسلہ میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور علمائے کرام کو اس مقصد کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرنا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمِ اسلام میں اپنے ایجنٹوں اور لابیوں کے ذریعے فکری انتشار بپا کیے ہوئے ہے، اسلام کے اجتماعی نظام کے نفاذ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، دینی قوتوں کو منتشر رکھنا چاہتا ہے، کشمیر کو تقسیم کر کے وہاں اپنا فوجی اڈا قائم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلیاں کر کے اسے ایک سیکولر ریاست کی حیثیت دینے کے درپے ہے، اور قادیانیت جیسے گمراہ گروہوں کی آبیاری کر رہا ہے۔ ان حالات میں اگر علماء نے اپنی ذمہ داری محسوس نہ کی اور مسلمانوں کو منظم و بیدار کرنے کی محنت نہ کی تو وہ اپنے دینی فرائض سے عہدہ برآ نہیں ہو سکیں گے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں مستحکم اسلامی حکومت کے قیام میں رکاوٹ ہے، فلسطین میں تحریکِ آزادی کو کچلنے کے لیے یاسر عرفات سے سازباز کر چکا ہے، صومالیہ میں اپنے استعماری مقاصد کے لیے پاکستان کی فوج کو استعمال کر رہا ہے، اور عالمِ اسلام کے کسی ملک کو ایٹمی قوت کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ صورتحال علماء اور دانشوروں کے لیے لمحۂ فکریہ ہے اور انہیں آگے بڑھ کر اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی راہنمائی کرنی چاہیے۔
مولانا اللہ وسایا
عالمی مجلسِ تحفظِ ختمِ نبوت کے مرکزی راہنما مولانا اللہ وسایا نے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی طرف سے قادیانیوں کی پشت پناہی اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ پاکستان کی طرح بنگلہ دیش اور دیگر مسلم ممالک میں بھی امریکہ اپنے مقاصد کے لیے قادیانیوں کو آگے بڑھا رہا ہے اور ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عزائم کے بارے میں مولانا زاہد الراشدی نے جو تجزیہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے اور وقت کی آواز ہے، اس لیے تمام دینی جماعتوں کو اس مہم میں ورلڈ اسلامک فورم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔
حضرت شیخ الحدیث مدظلہ
علماء کنونشن کے مہمانِ خصوصی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم نے خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم کے اس ارشاد کا حوالہ دیا جس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہی وہ دو گروہ آئندہ چل کر مسلمانوں کے خلاف فریق بنیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش کریں گے اس لیے شروع میں ہی ان سے بچنے کی ہدایت فرما دی۔ لیکن ہم اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج یہودیوں اور عیسائیوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت عالمِ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے طور پر سامنے آیا ہے اور وہ مسلمانوں کو دینی اعتبار سے کچل دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں امریکی سازشوں کے مقابلہ میں اپنے دینی تشخص کے تحفظ کے لیے جو کچھ بس میں ہو کر گزرنا چاہیے۔
انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک بلبل اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ پر پھینکتی رہی، اس کے اس عمل سے آگ نہ بجھ سکتی تھی لیکن اس کے جذبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اس سے ضرور اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں اس بلبل سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور نتائج سے بے نیاز ہو کر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اس مہم میں ہر ممکن حصہ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عزائم کو بے نقاب کرنے اور عالمِ اسلام کو اس کے خلاف منظم کرنے کے لیے خطباء کو زبان کی قوت، اہلِ قلم کو قلم کی قوت، اور اہلِ مال کو مال کی قوت استعمال کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے تعاون کر کے مہم کو منظم کرنا چاہیے۔
مولانا محمد اجمل خان
خطیبِ اسلام مولانا محمد اجمل خان نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اکابر نے انگریزی استعمار کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ امریکہ بھی اس کا جانشین ہے اور انہی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے اور عالمِ اسلام کے بارے میں اس کے مکروہ مقاصد کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن اس نے دوہرا معیار اختیار کر رکھا ہے۔ افغانستان کے عوام جب تک روس کے خلاف نبرد آزما تھے، انہیں مجاہدین کہا جاتا تھا۔ لیکن روس کے سامنے ہٹتے ہی اب افغان مجاہدین مغرب کی نظر میں دہشت گرد بن گئے ہیں اور امریکہ ان ’’دہشت گردوں‘‘ کی حکومت قائم ہونے میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک نے بوسنیا، صومالیہ، فلسطین اور کشمیر بارے میں جو طرزعمل اختیار کر رکھا ہے اس سے ان کی جمہوریت پسندی اور انسانی حقوق کی قلعی کھل گئی ہے اور وہ اب زیادہ دیر تک دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی جمہوریت ایک غیر فطری نظام ہے جس نے انسانی معاشرہ کو اخلاقی انارکی سے دوچار کر دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔
اظہارِ تشکر
ورلڈ اسلامک فورم کے چیئرمین مولانا زاہد الراشدی نے علماء کنونشن میں شرکت پر اکابر علماء اور کراچی کے احباب کا، جبکہ میزبانی کے فرائض سرانجام دینے پر مجلسِ تحفظِ ختمِ نبوت کراچی کے راہنماؤں بالخصوص مولانا سعید احمد جلال پوری، مولانا محمد جمیل خان اور مولانا محمد انور فاروقی کا شکریہ ادا کیا۔
امریکی عزائم: ورلڈ اسلامک فورم کے زیر اہتمام دوسرا علماء کنونشن
ادارہ
عالمِ اسلام کے بارے میں امریکہ کے منفی عزائم اور پاکستان کے داخلی معاملات میں بڑھتی ہوئی امریکی مداخلت کے خلاف رائے عامہ کو ہموار اور منظم کرنے کی غرض سے ورلڈ اسلامک فورم کے زیر اہتمام علماء اور دینی کارکنوں کا دوسرا کنونشن ۱۲ جنوری ۱۹۹۴ء کو مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں منعقد ہوا جس میں موسم کی خرابی کے باوجود علماء اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن کی پہلی نشست کی صدارت پیر طریقت حضرت مولانا سید نفیس الحسینی مدظلہ العالی نے کی اور دوسری نشست شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کی زیرصدارت منعقد ہوئی۔ کنونشن سے ورلڈ اسلامک فورم کے چیئرمین مولانا زاہد الراشدی کے علاوہ مولانا عبد الحمید قریشی، علامہ محمد احمد لدھیانوی، ڈاکٹر غلام محمد، ماسٹر عنایت اللہ اور دیگر حضرات نے بھی خطاب کیا اور شاعرِ اسلام سید سلمان گیلانی نے اپنے پرجوش کلام سے حاضرین کو گرمایا۔
کنونشن میں رتہ دوہتڑ توہینِ رسالت کیس کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس سلسلہ میں بیرونی لابیوں اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے اس پروپیگنڈا کو بے بنیاد قرار دیا گیا کہ یہ کیس ذاتی دشمنی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ گوجرانوالہ کے علماء کی قائم کردہ ’’تحفظ ناموس رسالت ایکشن کمیٹی‘‘ کے سیکرٹری ڈاکٹر غلام محمد اور مولانا علی احمد جامی نے خود مذکورہ گاؤں رتہ دوہتڑ جا کر واقعات کی انکوائری کی ہے اور علاقہ کے عوام نے اس بارے میں مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ کیس میں گرفتار ملزمان نے مبینہ طور پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں شرمناک گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ کنونشن میں فیصلہ کیا گیا کہ کیس کے ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے خلاف ہائی کورٹ کے فل بینچ سے اپیل کی جائے گی اور لاہور کی سطح پر کیس کی پیروی کے لیے لاہور کے علمائے کرام کا ایک اجتماع بہت جلد منعقد کیا جائے گا۔
کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر نے کہا کہ قرآن کریم نے یہود و نصارٰی کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی کو نقصان دہ قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے، لیکن ہم نے اس حکمِ خداوندی کو نظرانداز کرتے ہوئے دوستی کے تعلقات قائم کیے جس کا خمیازہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ پورا عالمِ اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کی معاندانہ سازشوں میں جکڑا جا چکا ہے اور دنیائے کفر کی قیادت کرتے ہوئے امریکہ مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا اقدامات میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابر نے برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی تھی اور انہی کی قربانیوں کے نتیجہ میں برصغیر آزاد ہوا ہے لیکن آج برطانیہ کا جانشین امریکہ دوستی کے پردے میں ہم پر غلامی مسلط کر چکا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اکابر کے مشن اور روایات کو زندہ کرتے ہوئے امریکی تسلط کے خلاف جدوجہد کریں۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت عالمِ اسلام میں اسلام کے احکام کے عملی نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ حکمران طبقہ ہے جو مغربی نظامِ تعلیم کا پروردہ ہے اور مغرب کے مفادات کا محافظ ہے۔ اس کے سامنے جب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دورِ حکومت کی مثال پیش کی جاتی ہے اور خلفائے راشدین کی سادگی اور قناعت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس طبقہ کو اپنا موجودہ طرز زندگی اور مفادات خطرہ میں دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنے تعیش اور طبقاتی مفادات کو بچانے کے لیے نفاذِ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے نفاذ کی راہ میں فرقہ واریت حائل ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ فرقہ وارانہ اختلافات اسلام کے نفاذ کے مسائل پر نہیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ فرقہ واریت تو صرف برصغیر کے ممالک میں ہے اور اگر یہی نفاذ اسلام میں رکاوٹ ہے تو دنیا کے بیشتر مسلم ممالک جہاں فرقہ واریت نہیں ہے وہاں اسلام کیوں نافذ نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ بعض مسلم ممالک کا تو یہ حال ہے کہ وہاں علمائے کرام جمعہ کا خطبہ بھی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے، لیکن اسلام وہاں بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نفاذ اسلام کی راہ میں فرقہ واریت نہیں بلکہ حکمرانوں کے مفادات حائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ میں اسلام کے احکام کے نفاذ کے لیے پرخلوص جدوجہد کریں اور اس سلسلہ میں جو کچھ ان کے بس میں ہے اس سے گریز نہ کریں۔
حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے رتہ دوہتڑ کیس اور پاکستان کے داخلی معاملات میں امریکی مداخلت کا بطور خاص ذکر کیا اور علمائے کرام پر زور دیا کہ وہ اس سلسلہ میں امریکی عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے محنت کریں اور عوام کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کریں۔
مولانا زاہد الراشدی نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کا مقصد عالمِ اسلام کو سیاسی وحدت اور نفاذِ اسلام سے روکنا ہے، اور مغربی ممالک متحد ہو کر امریکہ کی قیادت میں ملتِ اسلامیہ کو نظریاتی استحکام، معاشی خود کفالت، ایٹمی توانائی اور سیاسی وحدت کی منزل سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک طرف انسانی حقوق کا واویلا کر رہا ہے اور دوسری طرف مسلم ممالک کو ایٹمی توانائی سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین، کشمیر، صومالیہ اور بوسنیا میں مغربی ممالک کا دوہرا کردار سامنے آ چکا ہے اور انہیں ان خطوں کے مظلوم مسلمانوں کے انسانی حقوق دکھائی نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ اسلامک فورم نے امریکہ کے عزائم اور کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں علماء اور دینی کارکنوں کے اجتماعات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو مسلسل جاری رہے گا، اور ہم جماعتی سیاست اور انتخابی سیاست سے الگ تھلگ رہتے ہوئے رائے عامہ کو امریکی عزائم کے خلاف منظم کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔
علمائے دیوبند اور ترجمۂ قرآنِ کریم
سید مشتاق علی شاہ
(۱) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا عبد الحق حقانیؒ
یہ ترجمہ تفسیر فتح المنان کے ساتھ ۸ جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ پہلی سات جلدیں ۱۳۰۵ھ سے لے کر ۱۳۱۳ھ کے عرصہ میں اور آٹھویں جلد، جو پارہ عم پر مشتمل ہے، ۱۳۱۸ھ میں مطبع مجتبائی دہلی سے شائع ہوئی۔ یہ تفسیر ’’تفسیر حقانی‘‘ کے نام سے مشہور ہے۔
(۲) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا عاشق الٰہی میرٹھی
یہ ترجمہ ۱۳۲۰ھ میں پہلی مرتبہ مطبع خیر المطابع لکھنؤ میں چھپا۔ اب پاکستان میں تاج کمپنی نے بھی شائع کیا ہے۔ اس کے ساتھ کہیں کہیں مختصر حواشی بھی ہیں۔ حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے مقدمہ قرآن میں اس کی تعریف کی ہے۔
(۳) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ
یہ ترجمہ بامحاورہ ہے اور علماء و عوام دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ ترجمہ مولانا نے اپنی مشہور تفسیر بیان القرآن کے ضمن میں کیا ہے۔ اسے پہلی مرتبہ ۱۳۳۶ھ میں مطبع مجتبائی دہلی نے بارہ جلدوں میں شائع کیا تھا۔ تفسیر کے علاوہ صرف ترجمہ مع مختصر فوائد بھی کئی قسموں میں تاج کمپنی اور کئی دوسری کمپنیوں نے شائع کیا ہے۔ شاہ عبد القادرؒ اور شاہ رفیع الدینؒ کے ترجمہ کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہے۔ کثرتِ اشاعت کے اعتبار سے اس کا نمبر دوم ہے۔ حضرت شیخ الہندؒ نے مقدمہ قرآن میں اس کی بھی تعریف کی ہے۔
(۴) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
حضرت شیخ الہندؒ نے اس ترجمہ کی ابتدا ۱۳۲۷ھ میں کر دی تھی لیکن تکمیل بحیرۂ روم کے جزیرہ مالٹا میں بزمانہ اسارت ہوئی۔ مولانا کا انتقال ۱۳۳۹ھ میں ہوا۔ انتقال کے بعد مدینہ پریس بجنور (انڈیا) کے مالک مولوی مجید حسن صاحب مرحوم نے شیخ الہندؒ کی اہلیہ مرحومہ سے اس کے حقوقِ اشاعت لے کر ۱۳۴۲ھ میں شائع کیا۔
(۵) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا فتح محمد صاحب جالندھریؒ
یہ ترجمہ اردو صرف و نحو کی مشہور کتاب ’’مصباح القواعد‘‘ کے مصنف کا ہے۔ ترجمہ عام فہم اور سلیلس ہے اور علمائے کرام کے نزدیک بھی معتبر اور مفید ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے لاہور کے مشہور ہندو تاجر کتب عطر چند کپور نے بھی اس کا ایڈیشن چھاپا تھا۔ اب تاج کمپنی پاکستان نے بھی اعلٰی معیار پر شائع کیا ہے۔ اس ترجمہ کا نام ’’فتح الحمید‘‘ ہے۔
(۶) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا محمد احمد سعید صاحب دہلویؒ
یہ ترجمہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحبؒ کی سرپرستی میں علماء کی ایک جماعت کے مشورے سے کیا گیا ہے۔ ترجمہ کا نام ’’کشف الرحمٰن‘‘ ہے۔ یہ ترجمہ سلیلس اور عام فہم ہے اور معمولی استعداد رکھنے والا شخص بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پندرہ پندرہ پاروں کی دو جلدوں میں دینی بکڈپو دہلی نے شائع کیا ہے اور پاکستان میں اس کی اشاعت مکتبہ رشیدیہ کراچی نے کی ہے۔
(۷) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ
یہ ترجمہ پہلی مرتبہ ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا۔ انجمن خدام الدین شیرانوالہ گیٹ لاہور نے اسے شائع کیا۔ ترجمہ بہت ہی آسان ہے۔
(۸) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا فیروز دین صاحب لاہوریؒ
یہ ترجمہ اردو لغت کی مشہور اور مقبول کتاب ’’فیروز اللغات‘‘ کے مرتب مولانا فیروز دینؒ کا ہے اور فیروز سنز نے ہی اسے شائع کیا ہے۔ ترجمہ مقبول ہے۔
(۹) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا سید ممتاز علیؒ دیوبندی
یہ ترجمہ قرآن کی توقیفی ترتیب کے مطابق نہیں ہے لیکن مکمل ہے۔ مترجم نے قرآن مجید کے علوم و مضامین کی ایک فہرست ’’تفصیل البیان فی مقاصد القرآن‘‘ کے نام سے برسوں محنت و مشقت کر کے ترتیب دی تھی۔ یہ ترجمہ اسی فہرست کے ضمن میں گیلانی پریس سے ۱۳۴۹ھ میں شائع ہوا۔ ترجمہ ابھی نامکمل تھا کہ مؤلف کا انتقال ہو گیا۔ باقی کام مولانا نجم الدین صاحب سیوہاروی نے مکمل کیا۔ یہ کتاب پہلے چھ جلدوں میں شائع ہوئی تھی، اب دو جلدوں میں دہلی سے شائع ہوئی ہے۔
(۱۰) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا عبد الحق عباسؒ
یہ ترجمہ ’’ترجمان القرآن‘‘ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں پہلے ہر آیت کے الفاظ کا ترجمہ الگ الگ کیا گیا ہے جس سے عام قاری یہ جان سکتا ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے۔ پھر سہولت کے لیے دوسری سطر میں بامحاورہ اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ مکتبہ علمیہ لاہور نے اسے نہایت اعلٰی معیار پر شائع کیا ہے۔ یہ الگ الگ پاروں کی صورت میں بھی شائع ہو رہا ہے۔
(۱۱) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا عبد الشکور لکھنؤیؒ
اس ترجمہ کا ذکر مولانا عبد الصمد صارم نے تاریخ التفسیر میں اور مولانا زاہد الحسینی نے تذکرۃ المفسرین میں کیا ہے۔
(۱۲) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجمین: (۱) مولانا خواجہ عبد الحئی فاروقیؒ، شیخ التفسیر جامعہ ملیہ دہلی (۲) حافظ نذر احمد (۳) حافظ مرغوب احمد (۴) حاجی عبد الواحد۔
یہ ترجمہ ’’درسِ قرآن‘‘ کے ساتھ ۷ جلدوں میں ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلوین بلڈنگ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس میں ہر آیت کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ الگ الگ کیا گیا ہے۔
(۱۳) ترجمہ قرآن مجید (کشمیری)
مترجم: مولانا سید میرک شاہ اندرابی تلمیذ علامہ انور شاہ کشمیری
اس ترجمہ کا ذکر ’’تعارف قرآن‘‘ از کرنل فیوض الرحمٰن میں موجود ہے۔
(۱۴) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا عبد الماجد دریابادی
یہ ترجمہ ’’تفسیرِ ماجدی‘‘ کے ساتھ ہی شائع ہوا۔
(۱۵) ترجمہ قرآن مجید (انگلش)
مترجم: مولانا عبد الماجد دریابادی
یہ ترجمہ ’’تفسیرِ ماجدی‘‘ (انگلش) کے ساتھ شائع ہوا ہے۔
(۱۶) ترجمہ قرآن مجید (سندھی)
مترجم: مولانا سید تاج محمود امروٹیؒ
یہ ترجمہ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوریؒ نے شائع کرایا تھا۔ کئی بار چھپ چکا ہے اور سندھ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔
(۱۷) ترجمہ قرآن مجید (سندھی)
مترجم: مولانا محمد مدنی سندھی
یہ ترجمہ کئی بار شائع ہو چکا ہے اور مقبول ہے۔
(۱۸) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا محمد علی صدیقی کاندھلویؒ
یہ ترجمہ تفسیر ’’معالم القرآن‘‘ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ابھی تک دس جلدوں میں دس پاروں کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔
(۱۹) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: علامہ سید عبد الدائم الجلالی
یہ ترجمہ صاف، سلیس، بامحاورہ اور عام فہم ہے اور تفسیر ’’بیان السبحان‘‘ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔
(۲۰) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی
یہ ترجمہ تفسیر ’’ہدایت القرآن‘‘ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ ترجمہ عام فہم ہے۔ اسے مکتبہ حجازیہ دیوبند ضلع سہارنپور نے شائع کیا ہے۔
(۲۱) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا حبیب احمد کیرانوی
یہ ترجمہ دو جلدوں میں کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے شائع ہوا ہے۔
(۲۲) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا قاضی عبید اللہ ڈیرویؒ
یہ تفسیر عبیدیہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ابھی اس کی صرف جلد اول شائع ہوئی ہے۔
(۲۳) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا قاضی اطہر مبارکپوری
یہ ترجمہ مکمل قرآن کا ہے لیکن راقم کی نظر سے نہیں گزرا۔ خیال ہے کہ ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ اس کا ذکر ’’تعارفِ قرآن‘‘ میں موجود ہے۔
(۲۴) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی
یہ ترجمہ ’’تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن‘‘ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ابھی تک پندرہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ تفسیر کے ساتھ ترجمہ عام فہم بامحاورہ اور تمام خوبیوں کا حامل ہے اور عوام و خواص میں یکساں مفید اور مقبول ہے۔ یہ ترجمہ شاہ ولی اللہؒ، شاہ عبد القادرؒ، شاہ رفیع الدینؒ، شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے تراجم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔
(۲۵) ترجمہ قرآن مجید (پشتو)
مترجم: مولانا فضل الرحمٰن پشاوری
اس کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کا ذکر ’’تذکرۃ المفسرین‘‘ میں موجود ہے۔
(۲۶) ترجمہ قرآن مجید (انگلش)
مترجمہ: اہلیہ حضرت مولانا عزیر گلؒ
یہ ترجمہ مولانا عزیر گلؒ اور ان کی اہلیہ نے تقریباً تیس سالہ محنت شاقہ اور مطالعہ کے بعد انگریزی زبان میں کیا جو دوسرے انگریزی تراجم سے کئی وجوہ سے ممتاز ہے۔ یہ ترجمہ فیروز سنز لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔
(۲۷) ترجمہ قرآن مجید (انگلش)
مترجم: محمد طفیل فاروقیؒ
یہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ شائع ہو رہا تھا کہ ۱۰ شعبان ۱۳۹۹ھ کو مترجم کا انتقال ہو گیا۔ ترجمہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کو اصل متن کے ساتھ رومن رسم الخط میں بھی تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے حاشیہ پر مختصر نوٹس بھی موجود ہیں۔
(۲۸) ترجمہ قرآن مجید (گجراتی)
مترجم: مولانا عبد الرحیم صادقؒ
(۲۹) ترجمہ قرآن مجید (پشتو)
مترجمین: مولانا فضل ودود ۔ مولانا گل رحیم اسماری
مولانا فضل ودود نے پہلے ۱۵ پاروں کا ترجمہ و تفسیر لکھی ہے اور باقی ۱۵ پاروں کا ترجمہ و تفسیر مولانا گل رحیم اسماری نے کی ہے (بحوالہ الرشید، دارالعلوم دیوبند نمبر)۔
(۳۰) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا شائع احمد عثمانی تلمیذ حضرت شیخ الہندؒ
یہ صرف پارہ عم کا ترجمہ ہے جو مطبع رحمانیہ مونگیر (بہار) سے ۱۹۱۷ء میں شائع ہوا۔ کرنل فیوض الرحمٰن نے پارہ عم کے علاوہ پارہ ۲۹، سورہ فاتحہ اور دیگر کئی سورتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔
(۳۱) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: مولانا عبد الباری فرنگی محلیؒ
یہ ترجمہ سلیس، عام فہم اور بامحاورہ ہے۔ اس کی دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں جو دو ابتدائی پاروں پر مشتمل ہیں۔ یہ ترجمہ ’’الطاف الرحمٰن بتفسیر القرآن‘‘ کے ساتھ شیخ الطاف الرحمٰن قدوائی نے ترتیب دے کر نامی پریس لکھنؤ سے ۱۹۲۵ء میں شائع کیا ہے۔
(۳۲) ترجمہ قرآن مجید (گجراتی)
مترجم: مولانا غلام صادق
یہ مولانا غلام صادق راندیری کی سعی ہے جو ترجمہ و تفسیر پر مشتمل ہے۔ یہ ترجمہ ۱۹۶۴ء میں مسلم گجرات پریس سورت سے شائع ہوا۔ دراصل یہ ترجمہ و تفسیر مولانا شمس الدین بڑودی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس ترجمے میں دو کالم کیے گئے ہیں، ایک میں عربی متن، دوسرے کالم میں ترجمہ ہے۔ فٹ نوٹس میں تفسیری فوائد ہیں۔ ترجمہ تمام تر شیخ الہندؒ اور حضرت تھانویؒ کے ترجموں سے مستفاد ہے۔ تفسیری فوائد مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے تفسیری حواشی سے ماخوذ ہیں۔ یہ ترجمہ دو جلدوں پر مشتمل ہے اور ۱۴۶۰ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ ابتدا میں ۱۱۸ صفحات پر مقدمہ ہے۔ ترجمے کی زبان رواں دواں اور ہلکی پھلکی ہے۔ گجراتی کے دوسرے تراجم کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ مقبول ہے (جائزہ تراجم قرآنی)۔
(۳۳) ترجمہ قرآن مجید (تلیگو)
مترجم: مولانا عبد الغفور کرلولی، فاضل دیوبند
تلیگو زبان میں یہ واحد تفسیر ہے۔ اس میں پہلے تلیگو رسم خط میں متنِ قرآن ہے، اس کے نیچے آیت متعلقہ کا ترجمہ ہے، پھر اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اس تفسیر کے تین پارے پہلی بار ۱۹۴۱ء میں شائع ہوئے تھے۔ اس کے بعد نواب مقصود جنگ افسر الاطبا کے پیش لفظ کے ساتھ مکمل دو جلدوں میں ۱۹۴۹ء میں شائع ہوئی (جائزہ تراجم قرآنی)۔
(۳۴) ترجمہ قرآن مجید (کنڑی)
مترجم کا نام معلوم نہیں
یہ ترجمہ اصل میں مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ہے جس کو کنڑی زبان میں منتقل کیا گیا ہے۔ ۱۶ پارے دارالاشاعت بنگلور سے ۱۹۶۶ء میں شائع ہوئے (جائزہ تراجم قرآنی)۔
(۳۵) ترجمہ و تفسیری نوٹس (فرانسیسی)
مترجم: ڈاکٹر حمید اللہ
اس کے مترجم ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی ہیں، آج کل پیرس میں مقیم ہیں، یہ ترجمہ اور تفسیری نوٹس ۱۹۹۰ء میں شائع ہوئے (جائزہ تراجم قرآنی)۔
(۳۶) ترجمہ قرآن مجید (اردو)
مترجم: حافظ نذر احمد
یہ ترجمہ عام فہم اور عربی سے ناواقف حضرات کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں پہلے ہر ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ الگ الگ پاروں کے علاوہ مکمل ایک جلد میں بھی مسلم اکادمی محمد نگر لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔
نوٹ:
تراجم کی مذکورہ تعداد مرتب کے علم کے مطابق ہے۔ اگر اہلِ علم کے پاس مزید معلومات ہوں تو وہ مطلع فرما کر شکریہ کا موقع عنایت کریں۔
مراجع و ماخذ
(۱) تاریخِ قرآن، قاری شریف احمد، مکتبہ رشیدیہ کراچی۔
(۲) تعارفِ قرآن، کرنل قاری فیوض الرحمٰن، مکتبہ مدنیہ لاہور۔
(۳) تاریخِ تفسیر، عبد الصمد صارم ازہریؒ، لاہور۔
(۴) تذکرۃ المفسرین، مولانا قاضی زاہد الحسینی، دارالارشاد اٹک شہر
(۵) منازل العرفان فی علوم القرآن، مولانا محمد مالک کاندھلویؒ، لاہور
(۶) ماہنامہ الرشید لاہور، دارالعلوم دیوبند نمبر۔
(۷) جائزہ تراجم قرآنی، مجلس معارف القرآن، دیوبند (انڈیا)