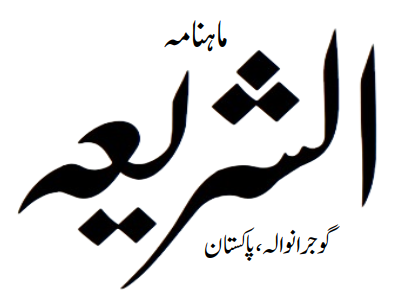(مجلسِ اقبالؒ لندن کے صدر جناب محمد شریف بقا کی تصنیف ’’اقبال اور تصوف‘‘ کی رونمائی کی تقریب سے ورلڈ اسلامک فورم کے سیکرٹری جنرل مولانا محمد عیسٰی منصوری کا خطاب۔)
صدر محترم، مہمانانِ خصوصی اور حاضرینِ مجلس!
آج کی یہ مجلس ہمارے محترم بزرگ اور دوست، اور مجلسِ اقبال لندن کے صدر جناب محمد شریف بقا صاحب کی مایہ ناز تصنیف ’’اقبال اور تصوف‘‘ کی رونمائی کے ضمن میں منعقد ہو رہی ہے۔ میں نے اخبار جنگ کی وساطت سے جناب بقا صاحب کے گرانقدر مضامین سے ہمیشہ استفادہ کیا ہے اور تقریباً ۱۵ سال سے بقا صاحب سے شناسائی و تعارف کا شرف بھی حاصل ہے۔ گزشتہ دنوں معلوم ہوا کہ اقبال اور تصوف کے موضوع پر آپ کی تازہ کتاب آئی ہے۔ میں کتاب حاصل کرنے کی فکر میں تھا کہ محترم بقا صاحب نے کرم فرمائی کی اور غریب خانہ پر تشریف لا کر کتاب عنایت فرمائی، ساتھ ہی آج کی مجلس میں خطاب کی دعوت بھی دی۔
کتاب کیا ہے، علوم و معارف کا گنجینہ ہے۔ اقبال کے کلام پر بقا صاحب کی جتنی گہری نظر ہے، اتنی ہی تصوف، علمِ کلام اور حضرات صوفیاء کرام کے احوال پر بھی نظر آئی۔ یہ چیز میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ کتاب میں انداز تحریر سلیس، عام فہم اور سادہ ہے۔ وحدۃ الوجود، مسئلہ جبر و قدر اور خودی جیسے معرکۃ الارا اور خالص علمی و فلسفیانہ مسائل کو اتنی سادہ زبان میں حل کیا ہے کہ اسے سہل ممتنع کہا جا سکتا ہے۔ نیز حضرات صوفیاء کرام کے احوال، ان کے افکار و معارف بڑے توازن و اعتدال اور جامعیت کے ساتھ کتاب میں آئے ہیں۔ میں اس بات کی شہادت دوں گا کہ اولیاء کرام کی خصوصیات، ان کے علوم و افکار اور امتیازات کو سمجھنے میں محترم بقا صاحب آج کے بیشتر علماء کرام سے زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ نیز اقبال کے اشعار، مضامین و نثری تحریروں کے انتخاب میں مصنف نے بڑی خوش ذوقی کا ثبوت دیا ہے۔ فاضل مصنف نے جس حسنِ نزاکت اور دیدہ دری کے ساتھ اقبال کے کلام کی تشریح و ترجمانی کی ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ کتاب نہ صرف تصوف پر اقبال کا نکتہ نظر سمجھنے کے لیے کافی ہے بلکہ اقبال کے پیغام کی مقصدیت و افکار و تصورات کو سمجھنے اور ساتھ ہی نفسِ تصوف اور حضرات صوفیاء کے احوال اور علوم و افکار کو سمجھنے کے لیے بھی بیش قیمت وسیلہ ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جن کتب سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا ہوں ان میں بقا صاحب کی یہ شاہکار تصنیف ’’اقبال اور تصوف‘‘ بھی شامل ہے۔ کتاب کے لفظ لفظ سے مصنف کی محنت اور قابلیت چھلکتی ہے۔ کتاب حشو و زوائد سے بالکل مبرا ہے۔ میں اتنی جامع، معلومات افزا اور بصیرت افروز کتاب لکھنے پر مصنف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ان کے پبلشرز نے کتاب کو طباعت، جلد و سرورق کے لحاظ سے جتنے حسین و خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اس کے لیے میر شکیل الرحمٰن صاحب اور ادارہ جنگ بھی بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔
اس کتاب کے ذریعے پہلی بار تصوف کے موضوع پر اقبال کے افکار و خیالات کا اتنا عظیم اور وقیع ذخیرہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہے اور حادثہ بھی کہ تاریخ کی اکثر عظیم شخصیات مظلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس ضمن میں جہاں اور بہت سے نام آتے ہیں اس میں علامہ اقبال بھی اس المیہ کا شکار ہیں۔ پاکستان میں اقبال پرستی کی ایک خاص فضا تیار کر کے اقبال فروشی کے کاروبار چمکائے گئے ہیں۔ اقبال کے افکار و آثار مسخ و مجروح شکل میں اس دھڑلے اور اس تکرار سے عام کیے گئے ہیں کہ حقیقی اقبال کی دریافت کارِ دشوار ہو گئی ہے۔ مرحوم آغا شورش کاشمیری نے کیا پتہ کی بات کہی ہے:
’’اقبال وہ شبلی نعمانی ہے جسے کوئی سلیمان ندوی نہ مل سکا۔‘‘
علامہ اقبال نے حافظ کی شاعری کے چند پہلوؤں پر تنقید کی تھی۔ اس کا سہارا لے کر علامہ کے نظریہ تصوف کے بارے میں شد و مد سے غلط فہمیاں پھیلائی گئیں اور انہیں تصوف کا مخالف مشہور کیا گیا۔ اس کتاب میں بقا صاحب نے وضاحت سے بتایا ہے کہ اقبال کس تصوف کے مخالف تھے اور کس تصوف کے موافق۔ بدقسمتی سے آج اقبال کا جانشین وہ طبقہ بن بیٹھا ہے جسے اقبال کے سوز و گداز، عشقِ نبویؐ اور اسلام کی انانیت و ابدیت پر یقین سے کوئی نسبت نہیں۔ جس کے نزدیک مغرب کی نقالی ہی ترقی کی معراج ہے۔ جو تصوف تو کیا اسلام اور اسلامی اقدار و روایات ہی سے باغی ہے۔ اس کے نزدیک اقبال کے کلام کا بہت بڑا حصہ منسوخ ہو چکا ہے جو تجدد پسندی اور مغربیت نوازی کے خلاف ہے۔ اسے صرف وہ چند اشعار یاد ہیں جو اقبال نے علماء سو یا جاہل صوفیا کے متعلق کہے ہیں۔ اس قسم کے چند اشعار کے حوالہ سے حضرات صوفیا اور تصوف کے خلاف اس قدر پروپیگنڈہ کیا گیا ہے کہ محترم بقا صاحب کی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں خود اقبال کو نفسِ تصوف کے معاند گروہ میں سمجھتا تھا۔ ’’اقبال اور تصوف‘‘ پڑھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ تصوف کے متعلق اقبال کا نکتہ نظر بلا کم و کاست وہی ہے جو ہر دور میں علماء محققین اور اسلام کی نابغہ اور جلیل القدر ہستیوں کا رہا ہے، اور اس میں انتہائی توازن و اعتدال ہے۔
اقبال کے افکار کا جائزہ لینے سے پہلے آئیے نفسِ تصوف پر ایک نظر ڈالیں۔ آج کے دور میں اسلام میں تصوف سے زیادہ شاید ہی کوئی مسئلہ متنازعہ فیہ ہو۔
- ایک طبقہ تصوف پر، اس کی تمام جزئیات کے ساتھ بلکہ ہر ہر دور میں وسائل و ذرائع کے طور پر جو جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، جن میں بڑی حد تک ان ممالک کے معاشرہ و ماحول، اس قدر کے مزاج و نفسیات اور تہذیب و تمدن کا دخل ہے، من و عن ایمان لانا ضروری سمجھتا ہے۔
- جبکہ دوسرا طبقہ نفسِ تصوف ہی کو اسلام کے خلاف سازش اور اسلام میں عجمی یا غیر اسلامی پیوند قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تصوف بدعت بلکہ دین کی تحریف و تنسیخ ہے جس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔
آئیے ہم قرآن و سنت، رسول اللہؐ کی سیرتِ طیبہ اور تاریخ کی روشنی میں اس مسئلہ کا جائزہ لیں:
جب ہم قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ، آپ کے اقوال اور احوال پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کے دو پہلو ہیں:
- ایک ظاہری احکام، نماز روزہ، ذکر و تلاوت، صدقہ و خیرات۔
- اور دوسرے باطنی کیفیات، اخلاص و احتساب، خشوع و خضوع، صبر و توکل، تسلیم و رضا۔
پہلے کو فقہ ظاہر کہا جا سکتا ہے اور دوسرے کو فقہ باطن قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن و سنت نے ہمیں مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی ہے۔ اس میں جہاں ظاہری احکام و اعمال داخل ہیں وہیں باطنی کیفیات، کمالِ ایمان، درجۂ احسان، تسلیم و رضا بھی داخل ہیں۔ اگر ان باطنی کیفیات کو ہم احسان و تزکیہ کے نام سے یاد کرتے یا اسے فقہ باطن کہتے ہیں تو اس شدید اختلاف کی نوبت نہ آتی۔ دورِ نبوت میں ہر مسلمان دین کے ظاہری و باطنی دونوں پہلوؤں پر مکمل طور پر عامل تھا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع، اخلاص و احسان اور رسولؐ کی محبت، آخرت کا شوق، استحضار، اخلاص و استقامت کا حصول، ساتھ ہی ریا، طمع، حبِ جاہ، دنیا کی محبت و حسد، تکبر و غرور جیسے رذائل و امراضِ باطنی کا علاج بھی ضروری سمجھتا تھا۔
اس باطنی پہلو کے حصول کے طرق و ذرائع کا نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑ گیا۔ چونکہ لفظ تصوف اور اس کی اصطلاحات و تعبیرات، اور اسی طرح وہ طرق و ذرائع جو تزکیہ باطن یا احسانی کیفیت کے حصول کے لیے بعد کے ادوار میں اختیار کیے گئے، کم از کم شروع کی ڈیڑھ صدی میں نہیں ملتے۔ اس لیے بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیر اسلامی چیز اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جس نے تصوف سے بدظن کیا وہ ہر دور میں بعض پیشہ ور صوفیا کا وجود ہے۔ چنانچہ مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاب ’’تزکیہ و احسان‘‘ میں لکھتے ہیں:
’’دوسری چیز جس نے اس حقیقت کو زیادہ غبار آلود کر دیا وہ پیشہ ور، جاہ طلب، حقیقت فروش، اور الحاد شعار فاسد العقیدہ نام نہاد صوفی ہیں جنہوں نے دین میں تحریف کرنے، مسلمانوں کو گمراہ کر کے معاشرہ میں انتشار پیدا کرنے، آزادی و بے قیدی کی تبلیغ کرنے کے لیے تصوف کو آلہ کار بنایا۔ اور اس (تصوف) کے محافظ و علمبردار بن کر لوگوں کے سامنے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہلِ غیرت اور اہلِ حمیت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے بدظن ہو گئی۔ کچھ غیر محقق صوفیا ایسے تھے جو اس شعبہ کی روح اور اس کے حقیقی مقاصد سے ناآشنا تھے۔ وہ مقاصد اور وسیلہ میں تمیز نہ کر سکے۔ بعض اوقات انہوں نے وسائل پر تو بہت اصرار کیا اور مقاصد کو نظرانداز کر دیا۔ اس شعبہ اور اس فن میں ایسی چیزیں داخل کیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس کو فن کی روح اور تن کا کمال قرار دیا بلکہ مقصود و مطلوب سمجھ بیٹھے۔‘‘ (ص ۱۸)
غرض ایسے صوفیا کی وجہ سے مخلصین اور باغیرت مسلمانوں کے ایک طبقہ میں نفسِ تصوف ہی سے دوری اور بُعد پیدا ہوا۔ اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ تصوف کے نام پر جو عجمی افکار و تصورات دین میں داخل کیے جا رہے ہیں اگر انہیں رد نہیں کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی صحیح صورت ہی مسخ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے دین کی تحریف و تبدیلی کے اندیشہ سے نفسِ تصوف ہی سے انکار کر دیا۔ بندہ کے نزدیک تصوف سے تنفر اور دوری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعد کے ادوار میں ان علماء نے، جن پر تصور کا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا، اپنی نیک نفسی اور حسنِ عقیدت کی بنا پر بعض اکابر صوفیا کے صراحتاً غیر اسلامی افکار و خیالات اور بدیہی طور پر غلط بلکہ خلافِ اسلام باتوں کو، جو ان حضرات سے اکثر حالتِ سکر و حالتِ جذب میں صادر ہوتی رہی ہیں، دور اَز کار تاویلات کے ذریعہ شریعت کے مطابق ثابت کرنا چاہتا۔ جیسے محی الدین ابن عربی، منصور حلاج اور مہدوی فرقہ کے بانی شیخ محمد جونپوری کے افکار و دعووں کو صراحتاً خلافِ شرع کہنے کے بجائے ان بزرگوں کے علم و فضل، زہد و تقوٰی اور بعض ظاہری و باطنی کمالات کی وجہ سے ان کی غلط سے غلط باتوں اور دعووں کو کھینچ تان کر شریعت کے موافق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعض علماء کا یہ طرز عمل خاص طور پر ہمارے اس دور میں تصوف کے لیے بہت بڑا حجاب بن گیا اور بعض حلقوں نے چند ایسی باتوں کو نہایت ہوشیاری سے نفسِ تصوف کے خلاف اور تصوف سے بدظن اور متنفر کرنے کے لیے بڑی بے رحمی سے استعمال کیا۔
جہاں یہ ایک ناقابلِ تردید تاریخی حقیقت ہے کہ دورِ صحابہؓ کے بعد اسلام کی اشاعت میں سب سے نمایاں کردار حضراتِ صوفیا کا رہا ہے، دنیا کے بیشتر ملکوں میں اسلام انہی پاک نفس اہل اللہ کے ذریعہ پھیلا ہے، وہیں دوسری جانب آج آپ کسی بزرگ کے مزار پر چلے جائیں تو وہاں جو کچھ ہوتا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھ کر آپ کہہ اٹھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مشہور عالم ربانی، تصوف کے امام اور اپنے وقت کے بہت بڑے محقق مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے اپنے آخری دور میں اعتراف کیا تھا کہ تصوف سے فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی بے حد و حساب ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی مدظلہ لکھتے ہیں:
’’تصوف کی تاریخ پر جن حضرات کی نظر ہے ان سے یہ بات مخفی نہیں ہو گی کہ مختلف زمانوں میں اس راہ سے کیسی کیسی گمراہیاں امت میں داخل ہوئی ہیں، اور آج بھی اپنے کو تصوف و صوفیا کی طرف منسوب کرنے والے حلقوں میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے تصورات اور اعمال اسلام و توحید کی بہ نسبت کفر و شرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے جنہیں واقفیت اور بصیرت دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ خانقاہی حلقوں میں اس قسم کی گمراہیاں زیادہ تر بزرگوں کے ساتھ عقیدت اور خوش اعتقادی میں غلو اور تعظیم میں افراط سے پیدا ہوئی ہیں۔‘‘ (تصوف کیا ہے؟ ص ۴۴)
یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے علماء محققین نے تصوف میں غیر اسلامی افکار و خیالات اور باطل نظریات و فلسفوں کو رد کیا ہے اور احسان و تصوف کو صاف و شفاف طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مولانا ندوی لکھتے ہیں:
’’اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر ملک میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جو دین کو مبالغہ کرنے والوں کی تحریف، باطل پرستوں کی غلط بیانیوں اور جاہلوں کی تاویلات سے پاک و صاف اور عجمیت و فلسفہ سے محفوظ کرتے رہے، بغیر کسی تاویل و تحریف کے خالص تزکیہ کی دعوت دیتے رہے، جس کا نام احسان اور فقہ باطن ہے۔ انہوں نے اس طبِ نبوی کی ہر زمانہ میں تجدید کا فرض انجام دیا۔‘‘ (ص ۱۸)
یقیناً آج بھی اس ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر دور کی طرح آج بھی غیر اسلامی چیزیں تصوف کا جزو بنتی جا رہی ہیں۔
اب آئیے اسلام میں لفظ تصوف اور اس کی تعبیرات کی درآمد کا سراغ لگائیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ لفظ تصوف اور اس کی بعض تعبیرات یونانی اشراقیت سے آئی ہیں، چنانچہ مشہور حکیم ابو ریحان بیرونی لکھتا ہے:
’’صوف یونانی میں حکمت کو کہتے ہیں میں حکمت کو کہتے ہیں اور اسی سے فیلسفوف کو یونانی میں ’’پیلا سوپا‘‘ کہتے ہیں یعنی حکمت کا عاشق۔ چونکہ اسلام میں بعض لوگ ان کے قریب گئے اس لیے وہ بھی اسی نام (صوفیہ) سے پکارے گئے۔‘‘ (تصوف کیا ہے؟ ۔ ص ۹۴)
لفظ تصوف پر بحث کرتے ہوئے مولانا ندوی لکھتے ہیں:
’’سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا کہ اس لفظ کی حقیقت و مراد بتائیے؟ اس کا ماخذ و منبع کیا ہے؟ آیا وہ صوف سے ماخوذ ہے یا صفا سے نکلا ہے یا صفہ سے؟ یا وہ ایک یونانی لفظ صوفیا سے لیا گیا ہے جس کے معنی حکمت بتائے جاتے ہیں؟ آخر یہ لفظ کہاں سے برآمد کیا گیا اور کس طرح اس کا رواج ہوا؟ جبکہ نہ قرآن و حدیث میں اس کا وجود ملتا ہے، نہ صحابہ کرامؓ و تابعینؒ کے اقوال میں، نہ خیر القرون میں اس کا سراغ ملتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز جس کا یہ حال اور جس کی یہ تاریخ ہو، بدعت کہلانے کی مستحق ہے۔‘‘ (تزکیہ و احسان ۔ ص ۱۴)
درحقیقت تصوف اسلام کے مدمقابل اور شریعت کے مخالف اسی وقت بنتا ہے جب بے جا طور پر تصوف کے نام پر یونانی فلسفہ یا افلاطونی افکار یا اشراقیت کو رائج کیا جائے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں تصوف میں ان چیزوں کی آمیزش ہوئی ہے۔ بہت سے صوفیا یونان و اسکندریہ کے فلسفوں میں منہمک رہے ہیں۔ بعد کے دور میں ان حضرات کے فلسفیانہ افکار و خیالات کو بھی حسنِ عقیدت کی بنا پر دین یا تصوف سمجھ لیا گیا۔ چنانچہ علامہ سید سلمان ندویؒ لکھتے ہیں:
’’فلسفیانہ تصوف سے مقصود الٰہیات سے متعلق حکیمانہ خیالات رکھنا اور فلاسفہ کی طرح خشک زندگی اختیار کر کے ان کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس فلسفیانہ تصوف کا ماخذ یونان کا اشراقی اور اسکندریہ کا افلاطونی اسکول ہونا بعض قدیم علماء کے نزدیک بھی مسلم ہے۔‘‘ (تصوف کیا ہے؟ ص ۹۶)
شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اپنے رسالہ علم الظاہر والباطن میں باطنیہ و قرامطہ کی تلسیات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’اور اس قسم کی بہت سی باتیں متکلمین صوفیا کے کلام میں راہ پا گئیں۔‘‘
’’صوفیا میں بعض متکلمین کے طریق پر ہیں اور بعض فلاسفہ کے طریق پر اور ایک جماعت وہ ہے جو اہل حق کے مسلک پر ہے۔ جیسے فضیل اور وہ تمام لوگ جن کا امام قشیری نے رسالہ میں تذکرہ کیا ہے۔‘‘ (جلاء العینین ص ۳۵ ۔ تصوف کیا ہے؟ ص ۹۹)
معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اواخر سے ہی صوفیا کا ایک گروہ فلسفیانہ و کلامی مسائل کی بھول بھلیاں میں الجھ گیا تھا۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو انہیں باطل نظریات کے ہو کر رہ گئے تھے، جیسے کہ شیخ ابن سینا کے متصوفانہ فلسفہ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے یونانی فلسفہ، بدعتی جہمیہ کے خیالات، اور اسماعیلی (آغا خانی) قرامطہ باطنیہ کے ملحدانہ خیالات کا ملغوبہ قرار دیا ہے۔
بعض اکابر صوفیا کے فلسفیانہ مباحث میں مشغول رہنے کی سب سے واضح اور بدیہی مثال وحدۃ الوجود کا مسئلہ ہے جو اصلاً فلسفہ کا مسئلہ تھا مگر صدیوں تک اسے مذہبی رنگ دے کر بال کی کھال اتاری گئی۔ خیال آتا ہے کہ وحدۃ الوجود جیسے فلسفیانہ مسئلہ پر صدیوں تک ہمارے صوفیا کرام الجھے رہے اور ہمارے بہترین دماغ اس کی گتھیاں سلجھانے میں منہمک رہے۔ آج کے دور اور موجودہ حالات کے پس منظر میں یہ چیز ہماری سمجھ سے بالاتر نظر آتی ہے مگر ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ حضرات صوفیا کے وحدۃ الوجود جیسے فلسفیانہ مسائل میں اشتعال پر اعتراض کی بڑی وجہ اس دور کا پس منظر سامنے نہ ہونا ہے۔
دوسری صدی ہجری کے اواخر میں جب اسلام عرب سے نکل کر دور دراز علاقوں تک پھیلا، اس دور میں یونان، ہندوستان، ایران وغیرہ میں دیدانت فلسفہ و حکمت کا بڑا زور تھا۔ اس دور کا تعلیم یافتہ اور دانشور طبقہ انہی اصطلاحات و تعبیرات میں بات کہنے اور سمجھنے کا عادی تھا۔ اسے اس دور کی زبان یا اس دور کا میڈیا کہا جا سکتا ہے۔ اب اہل اسلام کے ایک طبقہ نے اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ زبان و اصطلاحات و تعبیرات استعمال کیں جو اس دور کی ضروریات اور اس دور کی زبان تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ کوئی کامیاب ہوا، کوئی پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے کسی حد تک مسئلہ کو سلجھایا اور کسی نے مسئلہ سلجھانے کی کوشش میں اسے اور الجھا دیا۔ محققین نے ہمیشہ صوفیا کے فلسفیانہ مباحث میں اشتعال سے اختلاف کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کو صوفیا کے جس مسئلہ سے زیادہ اختلاف تھا وہ یہی وحدۃ الوجود کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:
’’اس وحدۃ الوجود کی غایت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے عبد اور معبود، خالق اور مخلوق کا کردار، امر در امور، طاعت اور معصیت میں فرق نہیں کرتے۔‘‘ (طریق الہجرتین ص ۳۳۳)
’’ملاحدہ اہل وحدۃ الوجود کے نزدیک غیر حق عین حق میں گم ہو جاتا ہے بلکہ غیر حق کا وجود نفس حق کا وجود ہوتا ہے۔‘‘ (مدارج السالکین ج ۳ ص ۸۷ ۔ تصوف کیا ہے؟ ص ۱۲)
دوسری چیز جس میں اہلِ تصوف حدِ اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں وہ احسانی کیفیت کے حصول کے وسائل و ذرائع، یا تربیت کے ان طریقوں پر اصرار کرنا ہے جو مختلف زمانوں میں اہلِ تصوف نے اختیار کیے ہیں۔ جن کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کوئی طبیب حاذق مریض کے لیے دوا تجویز کرتا ہے جو ہر مریض کے مزاج اور موسم و احوال کے اعتبار سے بدلتی رہی ہے۔ چنانچہ مولانا اسماعیل شہیدؒ فرماتے ہیں:
’’صوفیا کے نفع بخش اشغال کی حیثیت دوا و معالجہ کی ہے کہ بوقت ضرورت ان سے کام لے اور بعد کو پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔‘‘ (ایضاح الحق الصریح۔ تصوف کیا ہے؟ ص ۷۱)
چنانچہ محققین نے تصریح کی ہے کہ ان اشغال یا اوراد و وظائف کی حیثیت احسانی کیفیت کے حصول کے لیے محض ذریعہ کی سی ہے۔ جیسے مریض کے لیے دوا، جو ہر شخص کے مزاج اور ہر زمانہ کے مطابق بدلتی رہتی ہے، جس پر اصرار کرنا یا یہ سمجھنا کہ ان اشغال کے بغیر قلوب کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا، صریح جہالت ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ قول جمیل میں فرماتے ہیں:
’’ہرگز خیال نہ کرنا کہ نسبت (خدا کا تعلق) بجز ان اشغال کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔‘‘
ان وسائل و ذرائع میں غلو کرنے یا انہیں ہی مقصودِ اصلی سمجھ لینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شریعت و طریقت کی دوئی کا ذہن بنتا ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ، جو خالص جہالت و کم فہمی پر مبنی ہے۔ چنانچہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ فرماتے ہیں:
’’ اور بعض جہلا جو کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، محض ان کی کم فہمی ہے۔ طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں۔ صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ قلب کا حال مثل آئینہ کے ہے۔ آئینہ زنگ آلود ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور گلاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق نجاست و طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کے پہچاننے کے لیے اتباعِ سنت کسوٹی ہے۔ جو متبع سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اگر مبتدع ہے تو محض بیہودہ ہے۔ خرق عادات تو دجال سے بھی ہوں گے۔‘‘ (تصوف کیا ہے؟ ص ۵۹)
اس بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ آج کل تصوف کی جن باتوں پر اعتراض و اشکال کیا جاتا ہے، محققین کے نزدیک وہ مقصود و مطلوب نہیں ہیں۔ ان کی حقیقت محقق صوفیا کے نزدیک بھی محض وقتی وسائل و ذرائع کی ہے۔ چنانچہ مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے اپنی کتاب ’’تزکیہ و احسان‘‘ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تصوف و شریعت کے مابین نزاع درحقیقت نزاع لفظی ہے۔ دراصل دوسری صدی ہجری میں اہل تصوف نے ایسی تعبیرات و اصطلاحات استعمال کیں جو بظاہر قرآن و سنت اور دور نبوت و دور صحابہ میں نہیں ملتیں۔ یہ تعبیرات و اصطلاحات اس دور کی فلسفیانہ زبان تھی۔
اس میں شبہ نہیں کہ تعبیرات کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے۔ تعبیرات و اصطلاحات مستعار لینے سے اس دور کے افکار و خیالات اور فلسفیانہ اثرات کا آنا ناگزیر ہے۔ چنانچہ تاریخِ تصوف کے لائق مصنف پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے تصوف کی یہ اصطلاحات و تعبیرات اور صفائی باطن کے ریاضات و مجاہدات ہندومت، بدھ مت، عیسائی و یہودی تصوف میں بھی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ لیکن محض ان تعبیرات کو اختیار کرنے کی وجہ سے نہ دین کے اس اہم جزو کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ تزکیہ و احسان سے بے اعتنائی برتی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مولانا ندوی فرماتے ہیں:
’’چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن دین کے ایک شعبہ اور نبوت کے ایک اہم رکن کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہے اور اس کو تزکیہ سے تعبیر کرتا ہے، اور ان چار ارکان میں اس کو شامل کرتا ہے جن کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ نبوت سے متعلق اور مقاصدِ بعثت میں شامل تھی، اور زبانِ نبوت اس کو ’’احسان‘‘ سے تعبیر کرتی ہے جس سے مراد یقین و استحضار کی وہ کیفیت ہے جس کے لیے ہر مسلمان کو کوشاں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ (بخاری و مسلم)‘‘ (ملخصاً ص ۱۴ ۔ ۱۵)
یہی وہ تزکیہ و احسان ہے جسے دوسری صدی ہجری میں تصوف کے لفظ سے یاد کیا جانے لگا۔ آگے مولانا ندوی مزید وضاحت سے فرماتے ہیں:
’’زیادہ مناسب تھا کہ ہم اس علم کو، جس کا نام تزکیہ نفس و تہذیبِ اخلاق ہے، تزکیہ و احسان ہی کے نام سے یاد کرتے یا کم از کم فقہ باطنی ہی کہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید اختلاف و نزاع کی نوبت ہی نہ آتی اور سارا جھگڑا ختم ہو جاتا، اور دونوں فریق جن کو اصطلاح نے ایک دوسرے سے برسرِ نزاع کر رکھا ہے، مصالحت پر آمادہ ہو جاتے۔‘‘ (تزکیہ و احسان ۔ ص ۱۶)
’’اگر اہلِ تصوف اس مقصد کے حصول کے لیے (جس کو ہم تزکیہ و احسان سے تعبیر کرتے ہیں) کسی خاص اور متعین راستے یا شکل پر اصرار نہ کرتے (اس لیے کہ زمان و مکان اور نسلوں کے مزاج و ماحول کے ساتھ اصلاح و تربیت کے طریقے اور ان کے نصاب بدلتے رہتے ہیں) اور وسیلہ کے بجائے مقصد پر زور دیتے تو اس مسئلہ میں آج سب یک زبان ہوتے ور اختلاف کا راستہ ہی باقی نہ رہتا۔‘‘ (ص ۱۷)
اس کے بعد مولانا ندوی نے فیصلہ کن بات فرما دی ہے جو میرے نزدیک انتہائی قرین انصاف اور حرفِ آخر ہے۔ فرماتے ہیں:
’’میں تزکیہ کی کسی خاص لگی بندھی اور متعین شکل پر زور نہیں دیتا، جس کا رواج عام ہوا اور جس کا نام آخری دور میں تصوف پڑا، اور نہ ہی تصوف کے حاملین میں سے سب کو ہر طرح کی غلط روی و غلط فہمی سے بری سمجھتا ہوں، اور نہ ان کو معصوم قرار دیتا ہوں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس خلا کو، جو ہماری زندگی اور ہمارے معاشرہ میں واقع ہو گیا ہے، جلد پُر کیا جائے اور تزکیہ و احسان اور فقہ باطن کو پھر سے تازہ کیا جائے، جس طرح ہمارے اسلاف نے اپنے اپنے زمانہ میں تازہ کیا تھا، اور یہ سب منہاجِ نبوت اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ بہرحال ہر دور میں اور ہر جگہ جہاں مسلمان بستے ہوں یہ کام ضروری ہے، اس لیے کہ حقیقت میں یہ خلا ایک عظیم خلا ہے اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کے اثرات و نتائج بہت دور رس ہیں۔
اپنے اپنے دور میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے والوں اور اس خدمت کے انجام دینے والوں پر تنقید کرنے والوں سے ایک عربی شاعر کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں ؏
اقلو علیھم لا ابا لابیکم من اللوم او سدوا المکان الذی سدوا۔
’’ان اللہ کے بندوں پر ملامت بہت ہو چکی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کی جگہ لینے والا اور درد کا مداوا کرنے والا کوئی ہے؟‘‘ (تزکیہ و احسان ص ۲۴۔۳۵)
اس ساری بحث کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ دین کے ظاہری و باطنی دونوں پہلو ضروری ہیں، اور تصوف اس دوسرے پہلو کے حصول کا محض ایک ذریعہ رہا ہے۔ محقق صوفیا کے نزدیک بھی تصوف کے اشغال مقصودِ اصلی نہیں بلکہ عشق و اخلاص اور خدا کا تعلق پیدا کرنے کے ذرائع ہیں۔ اسی طرح بیعت بھی ضروری و لازمی نہیں، محض اعتماد کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اور کسوٹی بہرحال قرآن و سنت ہی ہے، نہ کہ کوئی بزرگ یا ولی۔ لیکن آج کل بعض پڑھے لکھے لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا ہے کہ بڑی بے باکی سے نفسِ تصوف ہی کو زیغ و ضلال اور گمراہی کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف اس کوچہ سے نا آشنائے محض ہوتے ہیں بلکہ اسلام کے فرائض کی ادائیگی سے بھی کوسوں دور ہوتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام کی ۱۴ سو سالہ تاریخ سے اہل اللہ بزرگانِ دین اور ان کی کاوشوں کو الگ کر دیا جائے تو اسلامی تاریخ کے بہت بڑے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کیا کوئی ذی عقل اسے باور کر سکتا ہے کہ ۱۴ سو سال سے اسلام کے علمبردار اکابر اہل اللہ اور صوفیائے کرام سب کے سب اصل دین سے دور محض گمراہی میں رہے؟
اب آئیے کتاب اللہ کی طرف، قرآن عظیم رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے اور اس کا دعوٰی ہے ’تبیانا لکل شئی‘‘ یعنی انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، قرآن نے اسے مکمل طور پر بیان کر دیا، کوئی پہلو ادھورا نہیں چھوڑا۔ آئیے غور کریں کہ قرآن سے ہمیں اس ضمن میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔
تصوف اپنے انجام کے اعتبار سے رہبانیت سے زیادہ قریب ہے کہ تصوف میں غلو کا نتیجہ ہمیشہ ہر دور اور ہر ملت و مذہب میں رہبانیت کی صورت میں نکلا ہے۔ قرآنِ عزیز نے اپنے معجز انداز میں چند الفاظ میں رہبانیت کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد ہے:
ورھبانیۃن ابتدعوھا ما کتبنٰھا علیھم الا ابتغاء رضوان اللّٰہ فما رعوھا حق رعایتھا فاٰتینا الذین اٰمنوا منھم اجرھم وکثیر منھم فاسقون۔
(ترجمہ) ’’انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا، تو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی۔ ان میں جو لوگ ایمان لائے، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں۔‘‘ (از مولانا تھانویؒ)
یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ چند لفظوں میں رہبانیت کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نصف آیت میں رہبانیت کی پوری انسائیکلوپیڈیا کو بند کر دیا ہے۔ اس آیت سے اصولی طور پر چند امور کی طرف رہنمائی ملتی ہے: (۱) رہبانیت خدا نے فرض نہیں کی۔ (۲) انسانوں نے اسے خود اختیار کیا۔ (۳) جذبہ و نیت اچھی تھی یعنی خدا کے قرب و رضا کے حصول کی نیت رکھتے تھے۔ (۴) اس کے حدود کی رعایت نہ رکھ سکے۔ (۵) نتیجہ یہ ہوا کہ گمراہی و نافرمانی میں پڑ گئے، خدا سے قریب ہونے کے بجائے خدا سے دور ہو گئے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو تصوف کی تاریخ بھی یہی ہے کہ اللہ کے مخلص اور نیک بندوں نے احسانی کیفیت اور خدا کے تعلق و محبت کے حصول اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے اپنے اپنے دور میں عبادات و ریاضات، اذکار و ادوار کے مختلف طریقوں کو اپنایا۔ جب تک شریعت کی حدود میں رہے ان سے فائدہ اٹھایا، اور جب غلو آ گیا تو یہی چیزیں گمراہی و نافرمانی بنتی چلی گئیں۔
حضراتِ سامعین! اگرچہ تصوف پر تمہیدی کلام کچھ طویل ہو گیا ہے مگر علامہ کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے یہ تفصیل ضروری معلوم ہوئی۔ اب آئیے اس طرف کہ تصوف کے متعلق علامہ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ علامہ کی تحریروں کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں:
’’حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے مکتوبات میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف شعائر فقہ اسلامیہ میں خلوص پیدا کرنے کا نام ہے۔ اگر تصوف کی یہ تعریف کی جائے تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ راقم الحروف اس تصوف کو، جس کا نصب العین شعائر اسلام میں مخلصانہ استقامت پیدا کرنا ہو، عین اسلام جانتا ہے اور اس پر اعتراض کرنے کو بدبختی و خسران کے مترادف سمجھتا ہے۔ لیکن اہلِ نظر کو معلوم ہے کہ صوفیائے اسلام میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو شریعتِ اسلامیہ کو علمِ ظاہر کے حقارت آمیز خطاب سے یاد کرتا ہے اور تصوف سے وہ باطنی دستور العمل مراد لیتا ہے جس کی پابندی سے سالک کو فوق الادراک حقائق کا عرفان ہوتا ہے۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۲۸)
شاہ سلیمان پھلواری شریف کے نام مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’حقیقی تصوف کا میں کیونکر مخالف ہو سکتا ہوں کہ خود سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے تصوف کو کرات سے دیکھا ہے۔ بعض لوگوں نے ضرور غیر اسلامی عناصر اس میں داخل کر دیے ہیں۔ جو شخص غیر اسلامی عناصر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے وہ تصوف کا خیرخواہ ہے نہ کہ مخالف۔ انہی غیر اسلامی عناصر کی وجہ سے مغربی محققین نے تمام تصوف کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے اور یہ حملہ انہوں نے حقیقت میں مذہب اسلام پر کیا ہے۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۱۹۷)
ایک جگہ فرماتے ہیں:
’’تصوف کی ادبیات کا وہ حصہ جو اخلاق و عمل سے تعلق رکھتا ہے نہایت قابل قدر ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے طبیعت پر سوز و گداز کی حالت طاری ہوتی ہے۔ فلسفہ کا حصہ محض بے کار اور بعض صورتوں میں میرے خیال میں قرآن کے مخالف ہے۔‘‘ (اقبال و تصوف ۲۰۳)
سید نذیر نیازی کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:
’’اسلام کو فطرت کے طور پر Realize کرنے کا نام تصوف ہے اور ایک اخلاص مند مسلمان کا فرض ہے کہ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرے۔‘‘ (اقبال و تصوف)
اسی طرح ایک عزیز دوست کو لکھتے ہیں:
’’تصوف لکھنے پڑھنے کی چیز نہیں، کرنے کی چیز ہے۔ کتابوں کے مطالعے اور تاریخی تحقیقات سے کیا ہوتا ہے۔‘‘ (ص ۲۹)
ایک جگہ فرماتے ہیں:
’’خدا شناسی کا ذریعہ خرد نہیں عشق ہے، جسے فلاسفہ کی اصطلاح میں وجدان کہتے ہیں۔‘‘ (ص ۲۰۳)
رومی کے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔
ظفر احمد صدیقی کے نام اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’شریعت کو اپنے قلب کی گہرائیوں کے ساتھ محسوس کرنے کا نام طریقت ہے۔ جب احکامِ الٰہی خودی میں اس حد تک سرایت کر جائیں کہ خودی کے پرائیویٹ امیال و عواطف باقی نہ رہیں اور صرف رضائے الٰہی اس کا مقصد ہو جائے تو زندگی کی اس کیفیت کو بعض اکابر صوفیائے اسلام نے فنا کہا ہے، بعض نے اس کا نام بقا رکھا ہے۔ لیکن ہندی و ایرانی صوفیا جن سے اکثر نے مسئلہ فنا کی تفسیر ویدانت اور بدھ مت کے زیر اثر کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس وقت عملی اعتبار سے ناکارہ محض ہے۔ میرے عقیدے کی رو سے یہ تقسیم، بغداد کی تباہی سے بھی زیادہ خطرناک تھی اور ایک معنی میں میری تمام تحریریں اس تفسیر کے خلاف ایک قسم کی بغاوت ہیں۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۲۰۱)
علامہ نے متعدد جگہ بصراحت اس کی تکرار کی ہے کہ وہ کس تصوف کے خلاف ہیں۔ درحقیقت تصوف میں جو عجمی اثرات ہیں، خواہ وہ ہندی ویدانت کے ہوں، بدھ مت یا عیسائیت کے، یونانی اشراقیت کے ہوں یا ایرانی، یا ان لا یعنی فلسفوں کے جن میں ایران صدیوں تک مشغول رہا اور جس کی وجہ سے قدیم عربی لٹریچر میں ایران پر خاص طور پر عجم کا اطلاق ہوتا ہے، غرض ہر وہ چیز جو باہر سے درآمد کی جائے یا جمود کی طرف لے جائے یا جس میں شریعت و طریقت کی دوئی یا باطنیت کا شائبہ پایا جائے، علامہ کی طبیعت اس سے ابا کرتی ہے اور وہ اس کے خلاف احتجاج بلکہ جہاد اپنا فرضِ منصبی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ’’اقبال اور تصوف‘‘ کے مصنف جناب شریف بقا صاحب لکھتے ہیں:
’’بعض اہلِ طریقت یا اہلِ تصوف شریعت کے علم کو ظاہری علم اور تصوف و طریقت کے علم کو باطنی قرار دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں علمِ باطن علمِ ظاہر سے زیادہ اہم ہے۔ علامہ اقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل پیغام کو قرآن و سنت میں محفوظ خیال کرتے ہیں۔ علمِ مخفی یا علمِ باطن کے عقیدے کو ختمِ نبوت اور قرآنی ہدایت کی تکمیل کے منافی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ خدا کے اس آخری نبیؐ نے خدا کا پورا پیغام مسلمانوں کو پہنچا دیا تھا۔ اس لیے وہ کسی مخفی علم کو حضورؐ سے منسوب کرنا قرآنی اعلان کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ وہ شریعت و طریقت کو ایک ہی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے مرشد مولانا روم فرماتے ہیں کہ
’’شریعت ہمچو شمع است کہ رہ می نماید، چوں در راہ آمدی این رفتن تو طریقت است، چون بمقصود رسدی این رسیدن تو حقیقت است‘‘ (مثنوی دفتر پنجم)
’’شریعت راستہ دکھانے والی شمع کے مانند ہے، جب تو اس راہ میں آیا تو تیرا چلنا طریقت ہے، اور جب تو منزل مقصود تک پہنچ گیا تو تیرا یہ وہاں پہنچنا حقیقت ہے۔
یعنی شریعت روشنی ہے اور طریقت راستہ، جو منزل تک پہنچنے میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اس لیے شریعت و طریقت ایک دوسرے کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟‘‘
علامہ کے نزدیک نظری طور پر عربوں کا مزاج اسلام کے مطابق ہے اور عجمیت اسلام کی شکل مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے وہ اسلام میں عجمی اثرات کے سخت مخالف ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ عجمیت سے الرجک ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر سید یامین کے نام خط میں لکھتے ہیں:
’’میری رائے میں عجمیت ایشیا کے مسلمانوں کے لیے تباہی کا باعث ہوئی ہے۔ اس وقت اس باطل کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۲۰۱)
جب تک اسلام جزیرۃ العرب میں تھا اس میں حرارت و حرکت کا عنصر شامل تھا، لیکن جب دیگر ممالک تک پھیلا تو آہستہ آہستہ اس میں عجمی اثرات شامل ہوتے گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ؎
یہ امت روایات میں کھو گئی
حقیقت خرافات میں کھو گئی
علامہ، نیاز احمد کے نام خط میں لکھتے ہیں:
’’نہایت بے دردی سے قرآن اور اسلام میں ہندی و یونانی تخیلات داخل کیے جا رہے ہیں۔‘‘ (ص ۲۰۶)
اسی طرح ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:
’’عجمیت کی دھند سے باہر نکل کر عرب کے صحرا کی شاندار دھوپ میں چلو۔‘‘
اور
شیخ احمد سید گردون جناب
کا سب نور از ضمیرش آفتاب
با مریدے گفت اے جان پدر
از خیالات عجم باید حذر
شیخ احمد رفاعیؒ ایک عظیم المرتبت بزرگ تھے۔ سورج ان کے ضمیر سے اکتساب نور کرتا، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے مرید سے کہا، بیٹا تجھے عجمی خیالات سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں:
وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد
محبت میں یکتا حمیت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا
یہ سالک مقامات میں کھو گیا
ایک جگہ لکھتے ہیں:
’’تصوف غیر اسلامی عنصر سے خالی نہیں اور میں مخالف ہوں تو صرف ایک گروہ کا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیعت لے کر دانستہ و نادانستہ ایسے مسائل کی تعلیم دی جو مذہبِ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۳۲)
شیخ محی الدین ابن عربی جنہوں نے ساتویں صدی ہجری میں خالق و مخلوق کے اتحاد کو تصوف کا جزو لاینفک بنا دیا تھا، ان کے بارے میں علامہ لکھتے ہیں:
’’مسلمانوں اور ہندوؤں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب ذہنی مماثلت ہے۔ جس نکتہ خیال سے شری شنکر نے گیتا کی تفسیر کی، اسی نکتہ خیال سے شیخ محی الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی۔ انہوں نے مسئلہ وحدۃ الوجود کو اسلامی تخیل کا جزو لاینفک بنا دیا۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۳۶)
وحدۃ الوجود کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں:
’’ہمہ اوست مذہبی مسئلہ نہیں فلسفہ کا مسئلہ ہے۔ وحدت و کثرت کی بحث سے اسلام کو کوئی سروکار نہیں۔ اسلام کی روح توحید ہے اور اس کی ضد کثرت بلکہ شرک ہے۔ وہ فلسفہ و مذہبی تعلیم جو انسان کی شخصیت کی نشوونما کے منافی ہو، بے کار چیز ہے۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۳۶)
سراج الدین پال کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل میں باطنی معنی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل کو مسخ کر دینا ہے (جیسا کہ قرامطہ کے طرزعمل سے ثابت ہے)۔ یہ نہایت عیارانہ طریقہ تنسیخ ہے۔‘‘ (ص ۲۰۳)
خواجہ حسن نظامی کے نام اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں:
’’رہبانیت عیسائی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر قوم میں پیدا ہوئی ہے اور ہر جگہ اس نے قانون اور شریعت کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرنا چاہا ہے۔ اسلام درحقیقت اسی رہبانیت کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۲۰۲)
علامہ کا اسلام کی صلاحیت پر اعتماد اور اذعان کا یہ عالم تھا کہ ایک مجلس میں:
’’ہم نے آپ سے دریافت کیا، فوق البشر کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے ہر صحیح مومن فوق البشر ہے۔ اسلام وہ سانچہ ہے جس میں فوق البشر ڈھلتے ہیں ۔۔۔۔ کہنے لگے ہیرو کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان جس کے اعمال و افعال نوع انسانی کے لیے چشمہ ہائے زندگی جاری کرنے والے ہوں۔ شخصیت پرستی (Heroworship) ہندو قوم کی امتیازی صفت ہے، مگر اسلام اس کے خلاف ہے۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۲۰۰)
علامہ ہمیشہ ان علمائے حق اور صوفیائے عظام کے بڑے مداح اور دل سے قدردان رہے جنہوں نے تصوف کو شریعت کی حدود میں رکھا۔ ایسے علما و بزرگان دین سے بصد ادب ملتے اور ان کے مزارات پر بصد شوق و ادب حاضری دیتے، ان کے کارناموں سے مسلمانوں کے دلوں کو گرماتے، اپنے آخری دنوں میں مولانا ابوالحسن علی ندوی (جو ان دنوں نوعمر تھے) سے ملاقات کے دوران فرمایا:
’’اسلام اپنے پیروؤں میں عملیت اور حقیقت پسندی پیدا کرتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی تجدید و احیا کی بات نکلی تو فرمایا، شیخ احمد سرہندیؒ اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور سلطان محی الدین عالمگیر کا وجود اور ان کی جدوجہد نہ ہوتی تو ہندوستانی تہذیب و فلسفہ اسلام کو نگل جاتا۔‘‘ (اقبال و تصوف)
ایک جگہ اکبر الٰہ آبادی کے نام خط میں لکھتے ہیں:
’’مجدد الف ثانیؒ اور مولانا اسماعیل شہیدؒ نے اسلامی سیرت کے احیا کی کوشش کی مگر صوفیا نے اس گروہِ احرار کو کامیاب نہ ہونے دیا۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۳۷)
جاوید نامہ کے اخیر میں خطاب بہ جاوید کے عنوان سے چند باتیں جاوید کے لیے لکھی ہیں۔ ان میں ایک جگہ علامہ نے چودھری محمد حسین سے کہا:
’’عصرِ حاضر میں قحط الرجال ہے اور مردانِ خدا کا ملنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تمہیں کوئی صاحبِ نظر مل جائے گا۔ اگر نہ ملا تو تم میری ہی نصائح پر عمل کرنا۔ پھر کہنے لگے، میرے مرنے کے بعد جاوید جوان ہو تو اسے ان اشعار کا مطلب سمجھا دینا۔‘‘
اب آخر میں علامہ کی ایک نصیحت سن لیجئے۔ اکبر الٰہ آبادی کے نام خط میں لکھتے ہیں:
’’کوئی فعل مسلمان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ کے سوا کچھ اور ہو۔‘‘ (اقبال و تصوف ص ۲۰۲)
حضرات! بندہ نے ’’اقبال اور تصوف‘‘ سے یہ چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ بندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا علامہ کی ان روشن تحریروں اور افکار کی روشنی میں کوئی ذی عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ علامہ نفسِ تصوف کے خلاف تھے؟ اور کیا آج کے اقبال شناسی کے دعوے داروں کو اقبال کے فکر و ذہن یا افکار و خیالات سے کوئی دور کی نسبت بھی ہے؟
الشریعہ کے مئی ۹۴ء کے شمارے میں محمد یاسین عابد صاحب کا مضمون بعنوان ’’گستاخِ رسول کے لیے سزائے موت اور بائبل‘‘ شائع ہوا تھا۔ ماہنامہ ’’المذاہب‘‘ لاہور کے ایڈیٹر جناب محمد اسلم رانا نے اس مضمون پر ہمیں زیر نظر تنقید لکھ کر بھیجی ہے جو کہ نذرِ قارئین ہے۔ نیز رانا صاحب کے نقطۂ نظر کی مکمل توضیح کے لیے ان کا المذاہب کے جولائی ۹۴ء کے شمارہ میں شائع ہونے والا مضمون بھی زیر نظر شمارہ میں شاملِ اشاعت ہے۔
جہاں تک ہم غور کر سکے ہیں، دونوں نقطہ ہائے نظر میں، درحقیقت، کوئی اختلاف نہیں۔ محمد یاسین عابد صاحب کے مضمون کا منشا یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی طرح موسوی شریعت میں بھی گستاخِ رسول کے لیے سزائے موت تھی، جیسا کہ استثنا ۱۷ : ۱۲۔۱۳ سے واضح ہے۔ جس میں یہ حکم ہے کہ کاہن اور قاضی کا کہا نہ ماننے اور گستاخی سے پیش آنے والے شخص کو جان سے مار دیا جائے۔ ظاہر بات ہے، نبی کا مقام و مرتبہ کاہن و قاضی سے بلند تر ہے، اس لیے اس کے گستاخ کی سزا بھی لازماً موت ہی ہو گی۔ ہاں، البتہ، اس سزا کے اثبات کے لیے ۱۔سموئیل باب ۲۵ میں بیان ہونے والے حضرت داؤد اور نابال کے قصہ سے استدلال، جیسا کہ اسلم رانا صاحب کی تنقید سے واضح ہے، درست نہیں ہے۔
دوسری طرف اسلم رانا صاحب نے اس پہلو کو واضح کیا ہے کہ موجودہ مسیحی دنیا کے ہاں گستاخی رسول کی کوئی خاص اہمیت نہیں، بلکہ بالکل بے قید آزادی اظہار رائے کے قائل جدید مغربی ذہن سے متاثر ہونے کی بنا پر ان کے ہاں بھی اس نوعیت کی ہر چیز ’’انسانی حقوق‘‘ میں شامل ہے۔ اور یہ چیز موسوی شریعت میں گستاخ رسول کے لیے سزائے موت کے اثبات کے منافی نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ دونوں نقطہ ہائے نظر، درحقیقت، ایک ہی مسئلے کے دو الگ الگ پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
مضمون میں حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار، جیسا کہ سیاق و سباق سے واضح ہے، یہودی و عیسائی لٹریچر کے تناظر میں ہے، اس سے کسی غلطی فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قرآن مجید بصراحت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرار دیتا ہے۔
ان ضروری تمہیدات کے بعد اب آپ اصل مضمون ملاحظہ کیجئے۔
(مدیر)
ان دنوں مسیحی اقلیت گستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کی مخالفت میں ادھار کھائے بیٹھی ہے تو مسلم علما گستاخ رسول کی سزا کے اثبات میں خوردبین کی مدد سے بائبل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
موقر جریدہ الشریعہ مئی ۹۴ء میں اسلامی نقطہ نگاہ کی حمایت میں ایک مضمون نظر سے گزرا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کاہن، قاضی اور والدین کی شان میں گستاخی کی سزا وارد ہے اور عہد کے صندوق (جسے قرآن مجید میں صندوق سکینہ پکارا گیا ہے، ۲۔بقرہ ۲۴۸)، لیکن خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بائبل گستاخِ رسول کی سزا کے ضمن میں یکسر خالی، کوری اور معرا ہے۔
مضمون میں داؤد اور نابال کے قصہ سے ’’گستاخ رسول کی سزا موت‘‘ کشید کرنا شدید غلط فہمی، اور اس بیان کو ٹھیک طور پر نہ پڑھنے اور نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے ہے۔ مضمون کا متعلقہ حصہ درج ذیل ہے:
’’حضرت داؤد علیہ السلام کا نبی اللہ ہونا انجیل سے ثابت ہے (عبرانیوں ۱۱ : ۳۲)۔ معون کے رہنے والے نابال نامی ایک شخص نے حضرت داؤدؑ کے متعلق گستاخانہ الفاظ ادا کیے کہ ’’داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟‘‘ اس کی خبر جب داؤد نبیؑ کو ہوئی تو زبانِ نبوت سے شاتِم رسول کے لیے قتل کے احکامات یوں صادر ہوئے۔‘‘
عبرانیوں کے خط سے داؤد کی نبوت ثابت کرنا کئی لحاظ سے محلِ نظر ہے۔ عبرانیوں کے نام خط کا مصنف گمنام ہے۔ پولوس، اپولوس، برنباس، لوقا، ٹموتھی، اکوئیلا، پرسیلا، ارسٹن، فلپ ڈیکن سبھی اس کے مصنف قرار دیے جا چکے ہیں۔ یہ جھگڑا آج تک طے نہیں ہو سکا ہے (وکلف بائبل کمنٹری، عہد جدید : ۱۴۰۳ کالم ۲)۔ اس لیے دیر بعد اسے سند فضیلت ملی۔ اکثر قدیم لوگ اسے پولوس کا خط سمجھتے رہے ہیں، چنانچہ انگریزی بائبلوں میں اس خط کو پولوس کے نام منسوب کر دیا گیا ہے (ڈملو صفحہ ۱۰۱۲ کالم ۱)۔ پروٹسٹنٹ اردو بائبلوں کی روش بھی یہی ہے۔ پرانی اردو بائبلوں میں اسے ’’کا خط‘‘ لکھا بھی ملتا ہے۔ پھر یہ خط مسیحیوں کے ہاں مستند، معتبر، کلامِ خدا اور الہامی تو ہو سکتا ہے، یہودیوں کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر داؤد کو (یہودیوں کا) نبی قرار دینا غلط ہے۔ کیونکہ داؤد کا ذکر بائبل کی مخصوص یہودی کتب مقدسہ (عہد عتیق) میں ہے جہاں داؤد کو نبی نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے یہودی داؤد کو نبی نہیں مانتے۔ ان کی نظر میں داؤد اسرائیل کا عظیم ترین بادشاہ تھا، عہد عتیق کی ایک اہم ترین شخصیت تھا (قاموس الکتاب صفحہ ۳۹۲ کالم ۱)۔ پادری ڈملو نے داؤد کو جنگجو، موسیقی کا ماہر، ولی، زبور نویس اور ’’خدا اس کے ساتھ تھا‘‘ لکھا ہے، نبی نہیں لکھا (تفسیر ڈملو صفحہ ۱۸۱ کالم ۱)
ازروئے بائبل داؤد خود نبی نہیں تھا، اس کے دور میں سموئیل اور ناتن نبی تھے۔ سموئیل نے داؤد کو بطور بادشاہ مسح کیا تھا (۱۔سموئیل ۱۶ : ۱۳)۔ ناتن نبی صلاح مشورے دیا کرتا تھا، مثلاً بت سبع کے معاملہ میں اس نے داؤد کو سرزنش کی تھی (۲۔سموئیل ۱۲ : ۹)۔
بائبل کی کتاب اول سموئیل باب ۲۵ میں داؤد اور نابال کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے۔ معون کا مکین مسمی نابال بڑا بے ادب، بدکار، خبیث اور احمق تھا۔ ہزاروں بھیڑوں بکریوں کا مالک تھا۔ تفاسیر میں بتایا گیا ہے کہ اس زمانہ کا رواج تھا اور فی زمانہ بھی یہی وطیرہ ہے کہ عرب ڈاکوؤں سے مال کی حفاظت کرنے والے، مالک سے اپنا حق الخدمت لیا کرتے ہیں۔ داؤد نے کوہ کرمل میں نابال کے ریوڑوں کی حفاظت کی تھی (۲۵ : ۷) جس کا صلہ لینے کے لیے اس نے اپنے جوان نابال کے پاس بھیجے کہ
’’ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو اس لیے کہ اہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔‘‘ (۲۵ : ۸)
یہ الفاظ بڑے صاف ہیں۔ داؤد کا لہجہ ایک دولت مند سے اس کے مال کی حفاظت کرنے کی مزدوری مانگنے کا ہے۔ یہ خطاب ایک نبی کا اپنے پیروکار سے نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہے۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے بیٹا نہیں۔ جواب میں نابال نے داؤد کو حسبِ عادت درشت زبانی کی تو داؤد کو اس کی ناشکری اور نا احسان شناسی پر بڑا غصہ آیا اور وہ قریباً چار سو جوان لے کر نابال کو سزا دینے چل پڑا۔ ان جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل کو داؤد کے حسن سلوک (۲۵ : ۱۵، ۱۶) کی ساری بات بتائی تو وہ خود داؤد کے پاس گئی۔
’’تو داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی، جو بیابان میں تھا، بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی۔ کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔‘‘ (۲۵ : ۲۱)
ابیجیل نے نابال کی خباثت اور حماقت کا بتا کر اس کے لیے معافی مانگی اور داؤد کو خونریزی سے روکا۔ غرضیکہ داؤد نبی نہیں تھا، اس نے بحیثیت نبی نابال سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ اس نے نابال کے جواب کو توہینِ نبوت اور گستاخی رسول نہیں سمجھا تھا۔ نابال نے بھی داؤد کو نبی سمجھتے ہوئے وہ الفاظ ادا نہیں کیے تھے۔ داؤد کو غصہ یہ تھا کہ ہم نے نابال کے ریوڑوں کی حفاظت کی، گویا رات دن دیوار بنے رہے، اور یہ شورید سر ہماری محنت کا بدلہ بدزبانی سے چکا رہا ہے۔
نابال کی موت میں بھی اس کی موہوم ’’گستاخی رسول‘‘ کا کچھ حصہ نہیں تھا۔ داؤد سے واپس ہو کر ابیجیل نابال کے پاس گئی تو وہ شراب کے نشہ میں دھت تھا۔ صبح کو اس کا نشہ اترا تو ابیجیل نے اسے سارا واقعہ سنایا:
’’تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور پتھر کی مانند سن پڑ گیا اور دس دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا‘‘ (۲۵ : ۳۷)
شاید مرگی کا دورہ اس کی موت کا سبب بنا تھا (اے نیو کیتھولک کمنٹری آن ہولی سکرپچرز۔ ۱۹۸۱، صفحہ ۳۱۷ کالم ۱)
قانون گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا تبار میں دل آزار بات کہنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔ پاکستان کی مسیحی اقلیت اس قانون کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ اسے انسانی حقوق کی مخالفت، آزادی فرد، فکر، مذہبی آزادی، اقلیتوں کے عقائد و عبادات کی آزادی، مسلّمہ بین الاقوامی حقوق اور اقوام متحدہ کے منشور انسانی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے شخصی آزادی پر قدغن بتایا جاتا ہے۔ اس قانون نے مسیحیوں کو امتیازات کا نشانہ بنایا ہے اور انہیں دوسرے تیسرے درجہ کے شہری بنا کے رکھ دیا ہے۔
مسیحی ماہنامہ ’’کاریتاس‘‘ لاہور مئی ۹۴ء میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ
- تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ ۲۹۵سی آئینِ پاکستان کے منافی ہے،
- اس سے اقلیتوں کے تحفظ کا عہد مجروح ہوتا ہے،
- یہ قانون شہریوں پر ناانصافی اور عدمِ تحفظ کے دروازے کھولتا ہے،
- حکومت کو سماجی انصاف اور معاشرتی برائیوں کے خاتمہ کی ذمہ داری سے بری الذمہ قرار دیتا ہے،
- آئینِ پاکستان میں شہریوں کو دی گئی اظہارِ رائے کی آزادی سے محروم کرتا ہے،
- آئینی شہری آزادیوں کو استعمال کرنے میں مانع ہے،
- یہ قانون انسانی حقوق کے عالمی منشور کی کئی دفعات اور سماجی حقوق اور انصاف کے کئی بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
اتنا کچھ پڑھ پڑھ کر میں حیرت میں ڈوبا جاتا تھا کہ یاخدایا! ایک ارب سے زائد انسانوں کی محبوب ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنے سے روکنے پر مسیحی آزادیٔ تحریر و تقریر سے یکسر محروم ہو گئے! بے چارے بے دست و پا ہو گئے! ان کی سوچ و فکر کی قوتیں شل کر دی گئیں! ان کی کتنی شہری آزادیاں بھاڑ میں جا گریں! یا الٰہی یہ کیا ماجرا ہے؟ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ مسیحی آہ و زاریوں کی بنیاد دراصل وہ اندازِ فکر ہے جس کی جڑیں مغربی افکار میں پیوست ہیں۔
اقوامِ مغرب کی سوچ کی راہیں متعین کرنے میں یونانی بت پرستی، یونانی مذہبی اقدار و شعائر، یونانی عقائد و عبادات، اور یونانی اور رومی تہذیب و ثقافت کا کردار بنیادی ہے، جسے تحریکِ اصلاحِ کلیسیا نے جلا و مہمیز بخشی تھی۔ بت پرستی میں انسانی اخلاق و اعمال پر کسی پابندی کا قطعی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بت پرست انسان جو کرے وہی اس کا مذہب ہوتا ہے، جو وہ کہے باون تولے پاؤ رتی بجا و درست ہوتا ہے۔ اس کا ہر ہر قول و فعل پابندی، احتساب، تنقید اور اچھائی برائی کے معیاروں سے ماورا اور بالاتر ہوتا ہے۔ بت پرستی انسان کو مادر پدر آزادی عطا کرتی ہے۔ بت پرستوں کی سوچ و فکر کے گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں۔ بت پرست اپنے خداؤں کو بھی نہیں بخشتے، انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔
عیسائیت اس طریقِ فکر میں مستغرق اور رنگی ہوئی ہے۔ یہ امور عیسائی ذہنیت کا بنیادی پتھر ہیں۔ چنانچہ ’’آرتھوڈاکس چرچ آف پاکستان کے تمام شرکائے کلیسیا کے نام کھلا خط‘‘ میں پادری خورشید عالم ڈی ڈی بشپ پریسیٹیرین چرچ آف پاکستان بتاتے ہیں کہ انگلستان کا بادشاہ ہو یا ملکہ وہ انگلستان کا مذہبی سربراہ اور پارلیمانی ’’قانونِ برتری‘‘ کے باعث ’’سردار اعلیٰ اور محافظ دین‘‘ ہے۔ اس کی سرپرستی میں برطانوی پارلیمنٹ نے مرد کی مرد سے بدفعلی کو جائز قرار دیا اور اس غیر فطری گناہ کو تعزیرات میں نظرانداز کر دیا۔ اس روسیاہی کو گناہ نہ ٹھہرانے کے لیے ایک ممتاز مذہبی رہنما انگلیکن کینن کہف مونٹ فائر نے جولائی ۱۹۶۷ء میں مسیح کے شادی نہ کرنے اور مجرد رہنے کی وجہ یہ بتائی کہ مسیح لونڈے بازی سے گزارا کر لیا کرتا تھا (نعوذ باللہ)۔
پچھلے سال برطانیہ کے روزنامہ ٹیلی گراف میں یہ خبر چھپی کہ ایک گرجا کے پادری نے اپنی کتاب میں بتایا کہ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس پر اس کے عقیدت مند دو پارٹیوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ایک منکرِ خدا کو پادری کے فرائض ادا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری پارٹی کا کہنا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ انکارِ خدا پادری کا ذاتی نظریہ ہے، ہم اس کی شخصی آزادی پر پابندی نہیں لگا سکتے۔
برطانیہ میں ’’گستاخِ مسیح‘‘ کا قانون موجود ہے۔ حال ہی میں بی بی سی پر دکھائی جانے والی فلموں کے بارے میں اس قانون کا ذکر آیا تو انسانی حقوق کے یورپی کمیشن نے سرکار برطانیہ کو اس قانون پر نظرثانی کا مشورہ دیا۔ مسلمانوں نے اس قانون کا دائرہ کار وسیع کرنے کا مطالبہ کیا۔ بحث بڑھی تو ایک ممتاز عیسائی رہنما بشپ آف ڈرہم نے کہا کہ ’’خدا کو گستاخی سے بچانا تضیع اوقات ہے۔‘‘ (ریکارڈر ۱۷/۳/۹۴)
Defending God from blasphemy was a waste of time.
اس سوچ کی تہ میں کارفرما یہ حقیقت ہے کہ بائبل خدا کو کوئی قابل احترام اور معزز ہستی پیش نہیں کرتی۔ لکھا ہے ’’خدا بھسم کرنے والی آگ ہے‘‘ (اثنا ۲ : ۲۴) ’’خدا دغا دینے‘‘ والا ہے (یرمیاہ ۴ : ۱۰) ’’خدا بیوقوف‘‘ ہے (کرنتھیوں ۲ : ۲۵)۔ عیسائی مسیح کو خدا اور بالکل ٹھیک ٹھاک مکمل اور خالقِ کائنات قادرِ مطلق خدا مانتے ہیں۔ ادھر ان کا ایمان یہ بھی ہے کہ ’’ہاں وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا‘‘ (۲۔کرنتھیوں ۱۳ : ۴)۔ ایک شخص جسے مسیح کے بارہ شاگردوں میں شامل ہونے کا بھی اعزاز حاصل نہیں، ڈنکے کی چوٹ رقم طراز ہے ’’میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا‘‘ (۲۔کرنتھیوں ۱۱ : ۵)
جن لوگوں کے ہاں خدا کی شان میں گستاخی کے ہر امکان کی کھلی چھٹی ہو، جن کی کتابِ مقدس انہیں خدا سے متعلق مذکورہ الفاظ کے استعمال کا نمونہ پیش کرتی ہو، ان کی نگری میں فکری و نظری آزادی کی حدود کی وسعت مسلمانوں کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی۔
دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں مغربی افکار و اثرات کا دور دورہ ہے۔ وہیں کی درسگاہوں کے تعلیم یافتہ یا متاثرین برسرِاقتدار اور ہر شعبہ حیات میں روح رواں ہیں۔ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے خودکشی پر سزا ختم کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ ایک مضبوط دلیل مطالعہ فرمائیے کہ ’’حکومت کو کسی بھی فرد کی شخصی آزادی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے‘‘ (نوائے وقت ۲۹/۴/۹۴)
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کو بھی دفعہ ۲۹۵سی کی مخالفت میں پیش پیش پا کر میں مزید حیران ہوتا ہوں۔ بالاخر یہ عقدہ بھی حل ہو کر رہا۔ اس کمیشن کا ترجمان ماہنامہ ’’جہد حق‘‘ اپریل ۹۴ء ہمارے سامنے ہے۔ اس کے مطالعہ سے مسیحی تصورِ حقِ آزادی کے سلسلہ میں مجھ پر چودہ طبق روشن ہو گئے۔ رپورٹ کا عنوان ہے ’’ژوب ڈویژن میں صوبہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں‘‘۔ ذیلی سرخی ’’حقِ آزادی کی تلفی‘‘ کے تحت لکھا ہے:
’’اپریل۔ صوبیدار خان، لورالائی، ۲/۴/۹۳ ۔ ٹیکس ادا کرنے سے انکار پر بلاجواز گرفتاری۔‘‘
’’جون۔ خداداد، موسٰی خیل، ۷/۶/۹۳ ۔ سرکاری کام میں مداخلت پر غیر قانونی گرفتاری۔‘‘
المذاہب: یعنی ٹیکس ادا کرنے سے انکار انسان کا ’’حقِ آزادی‘‘ ہے۔ سرکاری کام میں مداخلت کرنا بھی ’’انسانی حق‘‘ ہے، جرائم نہیں ہیں۔ ان کے ارتکاب پر بازپرس نہیں کی جانی چاہیے۔ یاللعجب!
میڈونا برطانیہ کی مشہور و معروف اخلاق باختہ فاحشہ ہے۔ اس نے اپنی جنسی کارگزاریوں پر باتصویر کتاب بعنوان ’’سیکس‘‘ (Sex) لکھی تو مذہبی، سماجی اور اصلاحی حلقوں کی طرف سے اس کی زبردست مخالفت کی گئی۔ اب پڑھیے کہ کمیشن کی زیرمطالعہ میں رپورٹ ذیلی سرخی ’’۷۔حکومت کی طرف سے آزادی اظہار کی خلاف ورزی‘‘ کے تحت لکھا ہے:
’’اپریل۔ میڈونا کی کتاب سیکس پر ۲۱/۴/۳۹ کو حکومتِ بلوچستان نے پابندی لگائی۔‘‘
المذاہب: ’’سیکس‘‘ کے تعارف کے بعد ہم ’’حکومت کی طرف سے آزادی اظہار کی خلاف ورزی‘‘ پر اظہار رائے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔
آخر میں ’’اقلیتوں کے حقوق کی خلاف روزی‘‘ پر نوحہ خوانی کیجئے:
’’نومبر۔ ۱۱/۱۱/۹۳ ۔ اوم پرکاش، لورالائی، صرف چار بوتل شراب رکھنے کے جرم میں گرفتار۔‘‘
امید واثق ہے کہ مندرجہ بالا شواہد کی روشنی میں قارئین کرام پر مسیحیوں کے حقِ آزادیٔ اظہار کا حدود اربعہ روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا ہو گا اور وہ خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا تبار میں حسبِ منشا اول فول بکنا مسیحیوں کا حقِ آزادیٔ اظہار ہے جس سے انہیں محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بصورتِ دیگر وہ لاہور کیتھیڈرل کے بشپ الیگزینڈر جان ملک کے الفاظ میں اقوامِ متحدہ تک سے اپروچ کریں گے۔
قانون گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کرانے کے لیے مسیحی بھائی سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ ان کی خدمت میں آکسفورڈ کے بشپ رچرڈ ہیریز کا قول بغرض غوروخوض تحریر ہے کہ:
’’گو گستاخی مسیح کا موجودہ قانون کئی پہلوؤں سے تسلی بخش نہیں ہے، تاہم اسے ختم کر دینے کا مطلب یہ ہو گا کہ اب ہمارے معاشرہ میں مذہب کا کوئی مقام نہیں رہا ہے۔‘‘ (ریکارڈر ۱۷/۳/۹۴)
بیت النصر اربن کوآپریٹو سوسائٹی کا قیام جمعہ یکم اکتوبر ۱۹۷۶ء کو مہاشٹر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ۱۹۶۰ء کے تحت عمل میں آیا۔ سوسائٹی ہذا کے قیام کا مقصد ہندوستان میں غیر سودی بینک کاری کے لیے نئی راہیں دریافت کرنا، سود کے لین دین کو چھوڑ کر مکمل طور پر غیر سودی بینک کاری کے خطوط پر کام کرنا، صاف اور پاکیزہ ماحول میں کم لاگت والے رہائشی مکانات کی تعمیر کرنا، مسلمانوں میں سرمایہ کاری کا رجحان پیدا کر کے ان کے قیمتی سرمائے کو محفوظ کرنا اور انہیں مالی فائدہ پہنچانا اور حلال آمدنی کے ذرائع کی تلاش کرنا۔
ابتدا میں بیت النصر کا کل سرمایہ صرف ۱۲۰۰۰ روپے تھا جو ۳۱ مارچ ۱۹۹۰ء تک ۱۶.۶۵ کروڑ تک پہنچ گیا۔ سوسائٹی نے اپنے کام کا آغاز دو ملازموں سے کیا تھا اور اب ان کی تعداد بڑھ کر ۱۰۰ ہو گئی ہے۔ اس طرح یہ ادارہ قوم کے کئی افراد کے لیے ذریعہ معاش بھی بنا ہوا ہے۔ ابتدا میں ماہم کے ایک فلاحی ادارے میسوک (MESOC) کے دفتر سے سوسائٹی کا آغاز ہوا اور فی الحال عروس البلاد بمبئی کے ۹ اہم کاروباری مقامات ماہم، زکریا مسجد، مدنپورہ، مورلینڈ روڈ، باندرہ (ایسٹ)، بھارت نگر، کرلا، دھاراوی اور چیتا کیامپ میں سوسائٹی کی شاخیں ہیں۔ علاوہ ازیں تھوڑے ہی عرصہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور شاخ کھلنے جا رہی ہے۔ ۳۱ مارچ ۱۹۹۰ء تک سوسائٹی کے شیئرز کا کل سرمایہ ۱۴،۵۲،۰۰۰ اور تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے بطور ڈپازٹ جمع تھے۔ ابتدا سے ۳۱ مارچ ۱۹۹۰ء تک سوسائٹی ۷۳۸۲ افراد کو ۳،۴۱،۳۳،۸۰۰ روپے قرض دے چکی ہے۔
بیت النصر کے ممبر کیسے بنیں؟
ہر اس شخص کے لیے جو سوسائٹی میں اپنی رقم جمع کرنا، قرض لینا، ضمانت دینا چاہتا ہے، سوسائٹی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ ممبر بننے کے لیے کم از کم ۱۰ روپے کے تین شئیرز (حصص) خریدنا ضروری ہے اور ایک روپیہ داخلہ فیس بھی دینا پڑتی ہے۔ اگر ممبر چاہے تو ۲ سال بعد اپنی ممبر شپ ختم کر کے شیئرز کی رقم واپس حاصل کر سکتا ہے۔ سوسائٹی کے تمام دفاتر میں مندرجہ ذیل ڈپازٹ اسکیموں کی سہولت حاصل ہے۔ مزید تفصیلات آپ سوسائٹی کی کسی بھی شاخ سے معلوم کر سکتے ہیں۔
اسپاٹ ڈپازٹ (Spot Deposit)
یہ روزانہ ڈپازٹ اسکیم ہے۔ یہ بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ (Current Account) کے مشابہ (قسم کا) کھاتہ ہے، البتہ اس میں آپ گھر بیٹھے بچت کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اکاؤنٹ کم از کم ۵ روپے سے کھول سکتے ہیں اور جب جتنی رقم چاہیں جمع اور نکال سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ کھولنے کے ایک ماہ بعد تک آپ اس اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکال سکتے اور تین ماہ بعد سے آپ کو اس اکاؤنٹ میں کم از کم ۱۰۰ روپے جمع رکھنے ضروری ہیں، ورنہ ۲ روپے فی ماہ سروس چارج لیا جائے گا۔ اس اکاؤنٹ کے لیے سوسائٹی کی جانب سے یہ سہولت ہے کہ ہمارا مقرر کردہ کلکٹر خود آپ کے مکان، دکان یا آفس میں آ کر رقم وصول کرتا ہے۔
سیونگ ڈپازٹ (Saving Deposit)
آپ یہ اکاؤنٹ کم از کم پانچ روپے سے کھول سکتے ہیں اور جتنی رقم چاہیں جمع کر سکتے ہیں اور جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں، اس میں کلکڑ کی سہولت نہیں ہے۔
ریکرنگ ڈپازٹ (Recurring Deposit)
اس ڈپازٹ کی کم از کم رقم ۲۵ روپے ماہانہ اور مدت ۲ سال ہے۔ مدت ختم ہونے سے قبل ضرورت پڑنے پر چند روز قبل آفس میں اطلاع دے کر رقم واپس لی جا سکتی ہے۔ ممبران کی سہولت کے لیے سوسائٹی کا مقرر کردہ کلکڑ ہر ماہ آپ کے مکان، دکان یا آفس سے رقم وصول کرتا ہے۔
فکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit)
اس ڈپازٹ کی کم از کم رقم ۱۰۰ روپے اور مدت ایک سال ہے۔ مدت ختم ہونے سے قبل بوقت ضرورت چند دن پیشتر دفتر میں اطلاع دے کر رقم واپس لی جا سکتی ہے۔
قرضہ جات کے لیے شرائط و ضوابط
سوسائٹی سے قرض حاصل کرنے کے لیے قرض خواہ کو مندرجہ ذیل شرائط پورا کرنا ضروری ہے:
(الف) سوسائٹی کے رجسٹرڈ ممبران ہی قرض کے لیے عرضی دے سکتے ہیں۔
(ب) سوسائٹی کے ان ممبران کو جن کا کھاتہ سوسائٹی کے پاس کم از کم ایک سال سے باقاعدہ جاری رہا ہو، زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار روپے قرض دیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہمارے بنائے ہوئے رہائشی مکان اور خاص قسم کی تجارت کے لیے ۲۵ ہزار تک قرض دیا جا سکتا ہے۔
(ج) نئے ممبران ممبرشپ حاصل کرنے کے تین ماہ بعد ہی قرض کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ شروع میں انہیں فی کس زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار روپے قرض دیا جا سکتا ہے۔
(د) قرض کی مطلوبہ رقم کے مطابق مندرجہ ذیل ۴ چیزوں کی ضمانت قبول ہو گی:
(۱) سونے کے زیورات (مالیت) کی ۸۰ فیصد رقم بطور قرض حاصل ہو گی۔
(۲) سوسائٹی اور اس سے منسلک ادارہ برکت انویسٹمنٹ کے کھاتے داروں کی ضمانت۔ یہ ضمانت کھاتے میں جمع شدہ رقم کی ۸۰ فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے (یہاں یہ دھیان میں رکھی جائے کہ ضامن حضرات اپنے کھاتے سے ضمانت شدہ رقم اس وقت تک نہیں نکال سکتے جب تک کہ قرض کی پوری رقم ادا نہیں کی جاتی)۔
(۳) ان پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کے اکویٹی شیئرز (حصص) پہ جو کہ بمبئی اسٹاک ایکسچینج کے تحت رجسٹرڈ ہوں۔ ایسے حصص کی موجودہ قدر (Value) کا ۵۰ فیصد قرض دیا جا سکتا ہے۔
(۴) ان اسکوٹر، موٹر سائیکل، آٹو رکشا اور ٹیکسی کے رہن پر (Hypothecation) جو کہ بمبئی RTO میں رجسٹرڈ ہوں اور دس سال سے زیادہ پرانی نہ ہوں، قرض دیا جائے گا۔البتہ مندرجہ بالا قسم کا قرض (الف) اسکوٹر اور موٹر سائیکل کے رہن پر بارہ ہزار روپے یا ان کی موجودہ قدر کے ۶۰ فیصد، ان میں سے جو بھی کم ہو، دیا جائے گا۔ (ب) آٹو رکشا اور ٹیکسی کے لیے پندرہ ہزار روپے یا ان کی موجودہ قدر کے ۶۰ فیصد، ان میں سے جو بھی کم ہو، دیا جائے گا۔
قرضہ جات پر معمولی سروس چارج لیا جاتا ہے جس کی مدد سے سوسائٹی کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ ۲۰ قسطوں میں ہونی چاہیے۔
بیت النصر کے دیگر ادارے اور ان کی اسکیمیں
بیت النصر گو کہ ایک اربن کوآپریٹو سوسائٹی ہے مگر بیت النصر گروپ میں تین اور مالی ادارے شریک ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس گروپ کے ماتحت دو اور ادارے عنقریب وجود میں آ رہے ہیں۔ موجودہ تین ادارے حسب ذیل طریقے پر کام کر رہے ہیں:
(۱) فلاح انویسٹمنٹ لمیٹڈ اور (۲) اتفاق انویسٹمنٹ لمیٹڈ
بیت النصر اربن کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کی طرح یہ دونوں کمپنیاں بھی لوگوں کو سودی نظام سے بچا کر جائز اور حلال طریقوں سے سرمایہ کاری کرنے اور آمدنی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اپریل ۱۹۸۳ء میں وجود میں لائی گئیں۔ دونوں کمپنیاں اپنے ممبران کو جن میں ڈاکٹر، وکیل، دیگر پیشہ ور یا ملازمت پیشہ قسم کے لوگ شامل ہیں، اپنے پاس جمع کیا ہوا سرمایہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے مختلف کمپنیوں کے شیئرز (حصص) میں لگا کر ان سے فائدہ حاصل کر کے نفع کی رقم ممبران میں تقسیم کرتی ہیں۔ ایسے افراد جو بیک وقت ۳۵،۰۰۰ روپے کی رقم ان کمپنیوں میں سے کسی ایک میں جمع کرتے ہیں، انہیں پورٹ فولیو مینیجمنٹ (Portfolio Management) کی خدمات مہیا کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں نے ایک جوائنٹ پورٹ فولیو مینیجمنٹ اسکیم (Joint Portfolio Management Scheme) بھی تشکیل دی ہے جس کا عین مقصد کم سے کم سرمایہ لگا سکنے والوں کو بھی شیئر مارکیٹ کے کاروبار سے متعارف اور مستفیض کرانا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے ہر ممبر ابتدا میں کم از کم صرف دس ہزار روپے جمع کر کے اسکیم میں شامل ہو سکتا ہے۔ موجودہ اسکیم کے تحت سرمایہ لگانے والوں کو ان کے سرمایے پر ہر سال ۳۰ فیصد کے حساب سے منافع دیا گیا۔ ان کاموں کے لیے شیئر مارکیٹ سے منسلک ماہرین کی خدمات اداروں کو حاصل ہیں۔
(۳) برکت انویسٹمنٹ کارپوریشن
فلاح انویسٹمنٹس اور اتفاق انویسٹمنٹس نے مل کر جنوری ۱۹۸۸ء کو برکت انویسٹمنٹس کارپوریشن جاری کیا۔ یہ کارپوریشن بھی بیت النصر سے منسلک ہے۔ رہائشی مکانات فراہم کرنے کے کاموں میں یہ بیت النصر کی شریک کار ہے۔ برکت انویسٹمنٹس کارپوریشن بیت النصر کے عملی تعاون سے اب تک نالا سوپارہ، ممبرا اور کوسہ میں رعایتی داموں پر غیر سودی قرض کے ساتھ کئی لوگوں کو رہائشی مکان (فلاٹس) مہیا کر چکی ہے۔ علاوہ ازیں اس ادارہ کی ایک فکسڈ ڈپازٹ اسکیم بھی ہے۔
اس اسکیم کے ماتحت آپ اپنا سرمایہ حقیقی املاک (Real Estate)، اجارہ (Leasing)، نفع و نقصان میں شرکت (Profit and Loss Sharing) جیسے جائز اور حلال کاروبار میں لگا کر ’’برکت‘‘ کی آمدنی میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔
(۱) ڈپازٹ کی کم از کم میعاد ایک سال ہو گی اور کم از کم دس ہزار روپے بطور ڈپازٹ قبول کیے جائیں گے۔
(۲) منافع ہر تین مہینے سے بھی دینے کی سہولت ہے۔
(۳) دو سال سے زائد عرصہ کے لیے ڈپازٹ رکھنے والے حضرات کو برکت انویسٹمنٹ کارپوریشن کے آئندہ ہاؤسنگ اسکیموں میں ۵ فیصد تک رعایت دی جائے گی۔
(۴) فکسڈ ڈپازٹ کے تقابل میں بیت النصر سے قرض (Loan) کی سہولیات مہیا رہیں گی۔
۸۹۔۱۹۸۸ء میں برکت انویسٹمنٹس میں اس اسکیم کے ماتحت ۴۱ ڈپازٹرز نے سولہ لاکھ چھپن ہزار روپے رکھے تھے جس پر انہیں ۱۹ فیصد نفع دیا گیا۔ اس اسکیم کو لوگوں کا اس قدر اعتماد حاصل ہوا کہ ۹۰۔۱۹۸۹ء میں اس کے ڈپازٹرز کی تعداد ۴۱ سے بڑھ کر ۳۱ مارچ ۱۹۹۰ء تک ۱۹۱ ہو گئی اور رقم بھی ۴۵ لاکھ روپے تک بڑھ گئی۔ اس سال کے لیے ۱۷.۵ فیصد نفع تقسیم کیا گیا۔