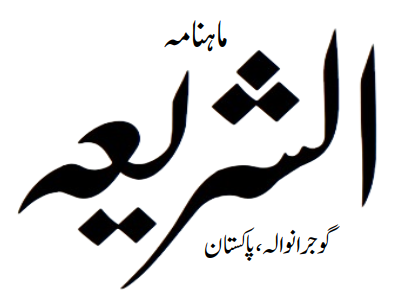جنوری و فروری ۲۰۱۱ء
حرفے چند
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ’’حجۃ اللہ البالغہ‘‘ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اعجاز کا یہ پہلو کہ فصاحت و بلاغت میں اس جیسا کلام لانا انسانی دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، اس پر نہ صرف ہر دور کے علما کرام نے دلائل و براہین کے ساتھ بات کی ہے بلکہ قرآن کریم کے وحی الٰہی ہونے سے انکار کرنے والے کسی بھی دور کے فصحاء و بلغاء اس چیلنج کا سامنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جبکہ اسی اعجاز کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سوسائٹی کی فلاح و بہبود اور ترقی و کامیابی کے لیے جو اصول و قوانین اور احکام و ضوابط بیان فرمائے ہیں، انسانی سوسائٹی اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود ان جیسا کوئی اصول یا حکم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کا ارشاد ہے کہ ان کے بعد آنے والا دور قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کے اس پہلو کے اظہار کا دور ہے اور وہ اپنی کتاب ’’حجۃ اللہ البالغہ‘‘ سے اسی علمی و فکری دور کا آغاز کر رہے ہیں۔
اسی بات کو فیلسوف مشرق علامہ محمد اقبالؒ نے ایک اور انداز میں بیان کیا ہے کہ آج کے دور کا مجدد وہ ہوگا جو اسلامی قوانین و احکام کا دنیا کے مروجہ قوانین و احکام اور معاشرتی اصول و ضوابط کے ساتھ موازنہ و تقابل کر کے اسلامی قوانین کی برتری اور افادیت و ضرورت کو ثابت کرے گا۔
اب سے دو صدیاں قبل ’’انقلاب فرانس‘‘ سے خالصتاً انسانی فکر کی بنیاد پر معاشرہ و تمدن کی تشکیل کے جس دور کا آغاز ہوا تھا وہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ کر اب واپسی کے راستے تلاش کر رہا ہے اور آسمانی تعلیمات کی ضرورت و اہمیت اور وحی الٰہی کی افادیت و تاثیر ایک بار پھر نسل انسانی کو اپنی طرف متوجہ کرتی نظر آنے لگی ہے۔
اس تناظر میں جن مسلم علماء نے اسلام کے معاشرتی کردار، اسلامی نظام و قانون کی ضرورت و افادیت، وحی الٰہی کی اہمیت و برتری اور عصر حاضر میں اسلام کے نفاذ و ترویج کی عملی صورتوں کو اجاگر کرنے کے لیے علمی و فکری محاذ پر کام کیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی علمی و فکری تحریک میں عملی طور پر شریک ہوئے ہیں، ان میں ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا نام اپنے معاصرین میں بہت ممتاز نظر آتا ہے اور ان کی علمی کاوشیں اس محاذ پر نئی نسل کے لیے یقیناً سنگ میل اور مشعل راہ ثابت ہوں گی۔
حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس شاہراہ پر ہمارے رفیق سفر تھے، مشفق راہنما تھے اور ہمدرد و معاون بھی تھے۔ ان کی جدائی نے تنہائی کے احساس کو اور زیادہ گہرا کر دیا ہے اور رکاوٹوں کی سنگینی فزوں تر دکھائی دینے لگی ہے۔ مگر سفر تو جاری ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا اور اس میں قدم قدم پر ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی یاد دل کو ستاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبولیت سے نوازیں اور سیئات سے درگزر کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔
آئے عشاق گئے وعدۂ فردا لے کر
اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ حیات و خدمات کا ایک مختصر خاکہ
ادارہ
نام: محمود احمد غازی (فاروقی)
والد: حافظ محمد احمد فاروقی ؒ
ولادت: ۱۸؍ ستمبر ۱۹۵۰ء
تعلیم
۱۔ حفظ قرآن (۱۹۵۸ء)
۲۔ آنرز عربی لینگویج (۱۹۶۶ء)
۳۔ درس نظامی (۱۹۶۶ء)
۴۔ آنرز فارسی زبان، پہلی پوزیشن گولڈ میڈلسٹ (۱۹۶۸ء)
۵۔ ایم اے عربی، پنجاب یونیورسٹی لاہور (۱۹۷۲ء)
۶۔ سر ٹیفکیٹ فرنچ زبان، فرنچ کلچرل سنٹر، اسلام آباد
۷۔ پی ایچ ڈی، (اسلامک اسٹڈیز)، فیکلٹی آف اورئنٹل لرننگ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور (۱۹۸۸ء)
منصبی ذمہ داریاں
۱) صدر،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد (۲۰۰۴ء تا ۲۰۰۶ء)
۲) نائب صدر،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد (نومبر ۱۹۹۴ء تا ۲۰۰۴ء)
۳) وفاقی وزیربرائے مذہبی امورحکومت پاکستان (اگست ۲۰۰۰ء تا اگست ۲۰۰۲ء)
۴) ممبر، قومی سلامتی کونسل، حکومت پاکستان (۱۹۹۹ء تا ۲۰۰۰ء)
۵) جج (عارضی)، شریعہ اپیلیٹ بنچ، سپریم کورٹ آف پاکستان (۱۹۸۸ء تا ۱۹۹۹ء)
۶) ممبر،اسلامی نظریاتی کونسل (۱۹۹۰ء تا ۱۹۹۳ء، ۱۹۹۷ء تا ۲۰۰۰ء)
۷) ڈائریکٹر جنرل ،شریعہ اکیڈمی ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد (۱۹۹۱ء تا ۲۰۰۰ء)
۸) ڈائریکٹر جنرل،دعوۃ اکیڈمی ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد (۱۹۸۸ء تا ۱۹۹۴ء)
۹) خطیب فیصل مسجد/ڈائریکٹر اسلامک سنٹر، فیصل مسجد، اسلام آباد (۱۹۸۷ء تا ۱۹۹۴ء)
ٍ۱۰) مدیر ’’الدارسات الاسلامیۃ‘‘ (سہ ماہی اردو مجلہ) ادارۂ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد
(۱۹۸۱ء تا ۱۹۸۷ء، ۱۹۹۱ء تا ۱۹۹۳ء)
۱۱) مدیر ’’فکر ونظر‘‘ (اردو سہ ماہی مجلہ)ادارۂ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد (۱۹۸۴ء تا ۱۹۸۷ء)
۱۲) پروفیسر ،ایسوسی ایٹ ڈین، کلیہ معار ف اسلامیہ، قطرفاؤنڈیشن، دوحہ۔
۱۳) چیئرمین شریعہ بورڈ ،اسٹیٹ بینک آف پاکستان ۔
۱۴) چیئرمین شریعہ ایڈوائزری سیل، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد
۱۵) چیئرمین شریعہ ایڈوائزری کمیٹی، تکافل پاکستان، کراچی (۲۰۰۵ء تا ۲۰۰۸ء)
علمی اداروں کی رکنیت
* ممبر، ورکنگ کمیٹی التجمع العالمی للعلوم المسلمین مکہ،سعودی عربیہ
* ممبر،الاتحاد العالمی للعلماء المسلمین (سرپرست شیخ یوسف القرضاوی) قاہرہ ،مصر
* ممبر، عرب اکیڈمی ،دمشق ، شام
* ممبر،سنڈیکیٹ، الرائد ایگری کلچرل یونیورسٹی ،راولپنڈی ،پاکستان (۲۰۰۶ء تا ۲۰۰۸ء)
* ممبر، ایگزیکٹو کونسل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد (۲۰۰۴ء تا ۲۰۰۷ء)
* ممبر، بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد (۱۹۹۱ء تا ۱۹۹۴ء)
انگریزی تصانیف
i. The Hijrah: Its Philosophy and Message for the Modern Man, 1980, 1988, 1999.
ii. An Analytical Study of the Sannsiyyah Movement of North Africa, Islamabad, 2001 (Based on Ph.D. Thesis).
iii. Renaissance and Revivalism in Muslim India: 1707-1867, Islamabad, 1998.
iv. The Shorter book on Muslim International Law (Edited and translated), Islamabad, 1998.
v. State and Legislation in Islam, Islamabad, 2006
vi. Prophet of Islam: His Life and Works (translated from French).
vii. Qadianism: Lahore, 1992
اردو کتب
ادب القاضی، اسلام آباد، ۱۹۸۳ء
مسودہ قانون قصاص ودیت، اسلام آباد، ۱۹۸۶
احکام بلوغت، اسلام آباد ۱۹۸۷ء
اسلام کا قانون بین الممالک، بہاولپور ۱۹۹۷، اسلام آباد ۲۰۰۷
محاضرات قرآن، الفیصل۔ لاہور ۲۰۰۴
محاضرات حدیث، الفیصل۔لاہور ۲۰۰۴
محاضرات فقہ، الفیصل۔لاہور ۲۰۰۵
محاضرات سیرۃ، الفیصل۔لاہور ۲۰۰۷
محاضرات شریعت وتجارت، الفیصل۔لاہور ۲۰۰۹
اسلامی شریعت اور عصر حاضر، انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، اسلام آباد، ۲۰۰۹
قرآن ایک تعارف، اسلام آباد ۲۰۰۳
محکمات عالم قرآنی، اسلام آباد ۲۰۰۲
امربالمعروف ونہی عن المنکر، اسلام آباد ۱۹۹۲
اصول الفقہ (ایک تعارف، حصہ اول ودوم)، اسلام آباد، ۲۰۰۴
قواعدفقہیہ (ایک تاریخی جائزہ، حصہ اول و دوم)، اسلام آباد ۲۰۰۴
تقنین الشریعہ، اسلام آباد ۲۰۰۵
اسلام اور مغرب تعلقات، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز،کراچی۔۲۰۰۹
مسلمانوں کا دینی و عصری نظام تعلیم، الشریعہ اکادمی، گوجرانوالہ۔۲۰۰۹
اسلامی بنکاری، ایک تعارف، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز،کراچی۔۲۰۱۰
فریضہ دعوت و تبلیغ، دعوۃ اکیڈمی، اسلام آباد۔۲۰۰۴ (اشاعتِ سوم)
اسلام اور مغرب، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز،کراچی۔۲۰۰۷
عربی تصانیف
تحقیق وتعلیق السیرہ الصغیرہ، امام محمد ابن حسن الشیبانی، اسلام آباد ۱۹۹۸ء
القرآن الکریم، المعجزۃ العالیۃ الکبریٰ، اسلام آباد ۱۹۹۴ء
یا امم الشرق (ترجمہ کلام اقبال)، دسمبر ۱۹۸۶ء
تاریخ الحرکۃ المجددیہ، بیروت ۲۰۰۹ء
العولمۃ،قاہرہ ۲۰۰۸ء
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمٰن المینویؒ (ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کے استاذ حدیث)
مولانا حیدر علی مینوی
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن المینویؒ ؒ نے ضلع صوابی ( صوبہ پختونخواہ) کے ایک دور افتادہ خوبصورت گاؤں ’’مینی‘‘ میں آنکھیں کھولیں جہاں کوہ مہا بن کا پرشکوہ نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ یخ بستہ ہوائیں کوہ مہابن کی فلک بوس وبرف پوش چوٹیوں سے پھسل کر اس گاؤں میں اترتی ہیں۔ یہاں ٹھنڈے پانی کے بل کھاتے چشمے، مالٹے اور خوبانی کے باغات کو سیراب کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قصبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سید احمد شہید ؒ اور ان کے ساتھیوں کے قافلے یہاں آکر رکے اور اس کی زمین شہیدوں کے لہو سے لالہ زار بنی۔
حضرت موصوف کا شمار دارالعلوم دیوبند کے ان فضلا میں ہوتا ہے جن کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ علم حدیث کے لیے وقف تھا۔ فراغت کے بعد آپ نے ایک مشہور ادارے دارالعلوم میرٹھ سے تدریس کی ابتدا کی اور پہلے ہی سال سے آپ کو حدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد تادم واپسیں آپ کے لیل ونہار اسی میں گزرے۔ ہندوستان سے واپسی پر آپ نے ملک کے بڑے بڑے اداروں میں حدیث کی خدمت کی۔ دارالعلوم چارسدہ، خیرا لمدارس مردان، جامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک میں پڑھاتے رہے، پھر مولانا غلام اللہ خانؒ کے شدید اصرار پر تعلیم القرآن راولپنڈی چلے آئے اور زندگی کے آخری دس سال یہیں گزارے۔ اس دوران میں اس چشمہ فیض سے ہزاروں طلبہ سیراب ہوئے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اکتساب علم کر کے اپنے علاقوں کو لوٹ گئے۔ درس کی عظمت اور وقار کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر درس کبھی زیادہ طویل ہو جاتا تو بھی طلبہ انتہائی مشقت کے باوجود ایک ہی انداز میں بیٹھے رہتے۔ عموماً دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے زمین پر ٹیک لگانے کی عادت تھی۔
احناف کے دلائل ذکر کرتے وقت قرون سابقہ کا منظر ہوتا۔ حیرت انگیز حافظے کے مالک تھے۔ آپ کے شاگرد ڈاکٹر مولانا محمود احمد غازیؒ فرماتے ہیں: ’’ حضرت پڑھاتے وقت جب کسی جگہ استشہاد کے لیے حافظ ابن حجر ؒ یا علامہ عینی کی لمبی لمبی عبارات پڑھتے تو اس وقت خیال ہوتا کہ روایت بالمعنی کے طور پر پڑھتے ہوں گے، لیکن فراغت کے بعد جب عبارات کا اصل مراجع سے تطابق کیا تو تعجب کی انتہا نہ رہی، عبارات میں من وعن الفاظ ہیں۔‘‘
حضرت شیخ کے لیل ونہار عمومی طور پر درس وتدریس میں گزرے او ر اس میدان میں آپ نے شاگردوں کی ایک پوری جماعت تیار کی، تاہم تصنیف وتالیف کے میدان میں بھی آپ کے کچھ نقوش موجود ہیں جن سے آپ کی یاد تازہ رہے گی۔
۱۔ اصول حدیث پرنہایت وقیع کتاب ’’جواہر الاصول‘‘ آپ کی گراں قدر تصنیف ہے۔ یہ کتاب پہلی بار راولپنڈی سے آپ کی زندگی ہی میں شائع ہوئی تھی۔ کتاب کے متعلق علامہ شمس الحق افغانیؒ فرماتے ہیں: ’’فقد طالعت الرسالۃ المسماۃ بجواہرالاصول لمولفہا العلام الجامع المعقول والمنقول والحاوی للفروع والاصول الشیخ المحدث عبدالرحمن المینوی‘‘۔
علامہ عبدالرحمن کیمل پوری ؒ فرماتے ہیں: حضرت مولانا عبدالرحمن مینوی ،شیخ الحدیث دارالعلوم چارسدہ کو بعض بعض مقامات سے دیکھا۔ حضرت موصوف علمی طبقہ میں خاص شہرت کے مالک ہیں۔ آپ نے نہایت عرق ریزی سے اس باب میں سعی فرما کر بکھرے ہوئے موتیوں کو یکجا جمع کردیا ہے اور اہل علم پر عظیم احسان فرمادیا ہے۔‘‘
مفتی اعظم مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں: ’’وبعد فانی رایت الرسالۃ الغراء جواہر الاصول من مواضع عدیدۃ فوجدتھا بحمداللہ حافلۃ لما لا بد منہ‘‘۔
۲۔ بخاری شریف کے ابتدائی تین ابواب پر ’’الکوثر الجاری علیٰ ریاض البخاری‘‘ کے نام سے دو جلدوں میں آپ کی شرح ہے۔ اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ احناف کے مذہب کو نہایت عمیق اور منطقی استدلال سے حل فرماتے ہیں۔ منطقی علوم میں حضرت کو امامت کا درجہ حاصل تھا۔
۳۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی میراث والی روایت پر ایک مستقل رسالہ ’’فیضان الباری فی حدیث ابن الحواری‘‘ لکھا ہے۔ قاضی شمس الدین ؒ نے الہام الباری میں اس حدیث کی تشریح میں جو تقسیم ذکر کی ہے، اس تقسیم پر حضرت شیخ کے کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے آپ نے یہ رسالہ لکھا۔ ( چند سال پہلے راقم نے اس مسودہ کو شائع کیاتھا۔)
۴۔ شدالرحال اور زیارات قبور پر بھی ایک اہم کتاب حضرت نے لکھی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا اصل مسودہ دریافت نہ ہو سکا۔ حضرت کی ذاتی لائبریری میں مجھے اس کتاب کا ایک کتابت شدہ نسخہ مل گیا، لیکن عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے اس کی لکھائی بہت مدھم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے پڑھنا دشوار ہے۔
۵۔ آپ کے ترمذی شریف کے افادات پرعلاقہ دیر کے جناب مولانا اعزاز علی، پی ایچ ڈی کے لیے ’’سنن ترمذی پر مولانا عبدالرحمن المینوی کے علمی کام کا تحقیقی جائزہ‘‘ کے عنوان سے پشاور یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے تحت اپنا مقالہ لکھ رہے ہیں۔ یہ تقریر تقریباً ساڑھے سات سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ صحاح ستہ پر آپ کے انتہائی جاندار اور محدثانہ افادات بھی آپ کے شاگردوں کے پا س محفوظ ہیں۔ حضرت شیخ کے ایک شاگرد مولانا اویس (سابق چیئر مین اسلامی ثقافت ڈنمارک) نے ان افادات پرکام کیا تھا جس کے لیے حضرت سے مسلسل رابطہ بھی رہا ۔ نہ معلوم کن وجوہات کی بنا پر یہ کام ادھورا رہ گیا۔
مولانا کا اسلوب تدریس انوکھی شان کاہوتا تھا۔ مشکل سے مشکل مقام کو آپ اتنی خوبی سے سمجھاتے کہ طالب علم کے سامنے سبق کا خلاصہ اور مغز تو آ ہی جاتا، متعلقہ بحث میں گہری بصیرت بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ طریقہ یہ ہوتا کہ کسی بات کو شروع کرتے تو فرماتے:
اس باب میں دس عنوانات ہیں: عنوان اول: امام بخاری نے یہاں تین ابواب قائم کیے ہیں ۔ ۲۔ ان تین ابواب سے امام بخاریؒ کی غرض۔ ۳: دوسرے باب پر وارد اشکال کاحل۔ ۴: سند کا بیان۔ ۵: چند اہم سوالات کا جواب ۔ ۶: ان تعبداللہ کانک تراہ میں درجات شرک کا بیان۔ ۷: احسان کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ ۸: ملائکہ پر ایمان کا مطلب ۔ ۹: قیامت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ ۱۰: آیت پر وارد اشکال کا حل۔
ہرکتاب میں عنوانات کا یہ سلسلہ رہتا۔ اس اسلوب پر لکھنا شاید آسان ہو، لیکن دوران درس میں اجمال وتفصیل کے عنوانات کو لف نشرمرتب کے ساتھ بیان کرنا غیر معمولی حافظے کاپتہ دیتاہے۔
حضرت مولانا کے اساتذہ میں سب سے پہلا نام تو شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمدمدنیؒ کاہے۔ آپ کے دوسرے اساتذہ میں شیخ الادب مولانا اعزاز علیؒ ، مولانا ابراہیم بلیاویؒ ، مفتی ریاض الدین بجنوریؒ وغیرہم ہیں۔
۱۹۷۰ء میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر حضرت شیخ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم
تو نے وہ گنج ہاے گراں مایہ کیا کیے
میری علمی اور مطالعاتی زندگی ۔ (ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا ایک غیر مطبوعہ انٹرویو)
عرفان احمد
(علم کی پختگی کے لیے باقاعدہ مطالعہ کرنے کی اہمیت سے انکار نہیں کیاجاسکتا۔ خاکسار بھی مختلف علوم اور مختلف موضوعات پر اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ آج سے دس برس پہلے پرانی کتابوں کی ایک دکان سے مجلس نشریات اسلام کی شائع کردہ کتاب ’’میری محسن کتابیں‘‘ اچانک دست یاب ہوئی۔ اس کتاب میں بیسویں صدی کے بعض بلند پایہ مشاہیر علم کے مطالعاتی تاثرات بیان کیے گئے تھے۔ مطالعہ کا ذوق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ کتاب ایک کلید اور محرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں شامل لوگوں کے طریق مطالعہ سے اپنے لیے مطالعے کے اصول اور طریقے اخذ کیے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے مجھ میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آج کے موجودہ دور کے ارباب علم کے بھی مطالعہ کے حوالے سے انٹرویوز کیے جائیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں نے آج سے تقریباً چار سال پہلے عصر حاضر کے اہل علم کے انٹرویوز کرنے شروع کیے جن میں زندگی کے مختلف شعبہ جات کے لوگ شامل ہیں۔ انہی ارباب علم میں ایک شخصیت جو اب ہم میں نہیں رہی، ڈاکٹر محمود احمد غازی کی تھی۔ مطالعے اور کتاب سے دلچسپی رکھنے والے سنجیدہ اہل علم اور شائقین کے لیے ان کے مطالعاتی ذوق کی داستان پر مشتمل یہ انٹرویو پیش خدمت ہے۔ عرفان احمد)
میری ابتدائی تعلیم روایتی انداز میں ہوئی جیسے میرے خاندان میں دوسرے لوگوں کی ہوئی تھی۔ پہلے میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد میں نے اپنے والد سے تھوڑی فارسی پڑھی۔ فارسی پڑھنے کے بعد پھر سکول میں داخل ہو گیا۔ تین چار سال سکول میں پڑھا، پھر اسکول کی کچھ تعلیم اطمینان بخش نہیں لگی تو میرے والد صاحب نے مجھے کراچی میں ایک دینی مدرسے میں داخل کروا دیا جہاں میں نے کوئی پانچ سال پڑھا۔ عربی وغیرہ اچھی سیکھ لی۔ میرے والد گورنمنٹ سروس میں تھے تو وہ پھر ۱۹۶۴ء میں اسلام آباد آگئے تو میں بھی ان کے ساتھ اسلام آباد آگیا۔ یہاں کوئی دینی تعلیم کا قابل اعتماد انتظام نہیں تھا، اس لیے تھوڑی تھوڑی وہ بھی چلتی رہی، لیکن اس کے ساتھ میں نے میٹرک کا امتحان بھی دے دیا۔ میٹرک کر نے کے بعد پھر میں نے انٹر میڈیٹ کرلیا۔ اسی دوران انٹر میڈیٹ کے امتحان کے بعد جب میں بی اے کے امتحان کی پرائیویٹ تیاری کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے تو پنڈی میں ایک سکول تھا، مدرسہ ملیہ اسلامیہ۔ مولانا عبد الجبار غازی مرحوم نے بنایا تھا۔ جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر بھی رہ چکے تھے جب مولانا مودودیؒ گرفتار رہے۔ کچھ عرصہ ان کے ہاں میں نے پڑھایا، لیکن میرا تاثر تھا کہ یہ ایسا ادارہ ہے نہیں جیسا کہ مولانا بنانا چاہتے تھے۔ اسی اسلامیہ مدرسہ میں، میں پڑھاتا تھا۔
مجھے مطالعہ کا شوق تھا، اس لیے میں چھٹی کے دن ادارہ تحقیقات اسلامی کی لائبریری میں چلا جایا کرتا تھا۔ سب لوگوں سے تعارف تھا۔ کسی اور دوست کے نام سے کتاب جاری کروالیا کرتا تھا۔ اسلام آباد میں ایک نیشنل سٹینڈرڈ لائبریری تھی اور وہ پاکستان کونسل برائے قومی یکجہتی لائبریری کہلاتی تھی۔ اس لائبریری میں بھی جایا کرتا تھا اور بہت سی کتابیں لاتا، لیکن وہاں عربی اور فارسی کی بجائے اردو، انگریزی کی کتابیں ملتی تھیں۔ میں فارسی جانتا بھی تھا اور بولتا بھی تھا۔ کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا اور کتابیں مجھے ادارہ تحقیقات اسلامی سے مل جایا کرتی تھیں توچھٹی کے دن میں پورا دن وہاں گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ میں وہاں گیا ہوا تھا۔ یہ بات تقریباً ۱۶؍ اکتوبر ۱۹۶۸ء کی ہے۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں چھٹی تھی۔ ۱۶؍ اکتوبر کو (شہادت لیاقت علی خان کی وجہ سے) میں صبح ہی ادارہ تحقیقات اسلامی کی لائبریری میں، جہاں Reading Hall تھا، وہاں چلا گیا۔ وہاں وہ ایک سرخ وسفید داڑھی والے صاحب بیٹھے ہوئے تھے جونفیس لباس اورخوبصورت عمامہ پہنے ہوئے تھے۔ بڑے خوبصورت اور وجیہ آدمی تھے۔ میں نے سلام کیا۔ قریب جا کر اندازہ ہوا کہ وہ نابینا تھے۔ عربی میں بات کرنے کا مجھے شوق تھا بچپن ہی سے جیسے کہ بچوں کو ہوتا ہے۔ قابلیت کے اظہار کا شوق بچپن میں زیادہ ہوتا ہے۔ سلام ودعا کے بعد عربی میں بات شروع کر دی۔ انھوں نے پوچھا تم کون ہو اور ایک آدھ سوال کیا تو میرے لہجے سے خوش ہوئے۔ پوچھا فارسی بھی جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جی۔۔۔ میں فارسی بھی جانتا ہوں۔ کتنی پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ فارسی میں نے کافی پڑھی ہے۔ پوچھا کلا م اقبال پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بہت پڑھا ہے۔ میں تقریباً اس دور میں اقبال کا حافظ تھا فارسی اور اردو میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی شعر سناؤ تو میں نے فارسی کے دو تین اشعار سنا دیے۔ ان کے سامنے ’’ارمغان حجاز‘‘ رکھی تھی۔ انھوں نے کہا کہ آخر میں جو رباعی ہے، اسے پڑھو۔ پہلی رباعی تھی ’’حرم از دیر دیگر رنگ وبو‘‘۔ کہا اس کا ترجمہ کرو۔ میں نے ترجمہ کردیا۔ بڑے خوش ہوئے۔ ترجمہ ٹھیک تھا، ان کو اچھا لگا۔
انھوں نے بتایا کہ میرا نام شیخ صاوی علی شعلان ہے۔ میں مصر کا مشہور شاعر ہوں اور مجھے حکومت پاکستان نے بلایا ہے کہ میں کلام اقبال کا عربی منظوم ترجمہ کروں گا توکیا تم میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو ؟میں نے کہا جی ہاں تو کہنے لگے کب سے؟ میں نے کہا کہ ابھی سے تو کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ پوچھا تو اسکول کا کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا، چھوڑدوں گا۔ اس پر بڑے خوش ہوئے۔ ان کو حیرت یہ بھی ہوئی اور شک بھی کہ کیسا آدمی ہے۔ ایک دو آدمیوں سے پوچھا تو انھوں نے یقین دلایا کہ یہ آپ کے ساتھ استعفا دے کر کام کرلے گا۔ تو میں نے وہاں جانا شروع کردیا اور اسکول میں استعفا دے دیا۔ مولانا غازی بہت ناراض ہوئے۔ انھوں نے بہت mindکیا لیکن میں نے ان کو اس کام کے بارے میں بتایا تو انھوں نے پوچھا کہ کیا تنخواہ ملے گی تو میں نے کہا کہ نہیں، تنخواہ کی فکر نہیں۔ اس طرح میں مدرسہ چھوڑ کر شیخ شعلان کے ساتھ لگ گیا۔ ان کے ساتھ کام کرنے میں کافی فائدے ہوئے۔ ایک تومیری عربی درست ہو گئی۔ پھر میں نے ان کے ساتھ کلام اقبالؒ ایک نئی ترتیب کے ساتھ پڑھا اور ہر مشق اور شعر کا عربی ترجمہ کر کے ان کو بتایا خاص طور پر اردو شعر کا۔ اور بھی بہت سی کتابیں پڑھیں اور اس طرح منتخب کلام کا ترجمہ ہوا، خاص طور پر علامہ اقبال کی فارسی مثنوی جو ہے، اس کا مکمل عربی ترجمہ ہوا، اس میں مدد کی۔ میں ترجمہDictateکردیا کرتا تھا، وہ اپنی برل مشین پر لکھ لیا کرتے تھے اور رات کو کہیں نظم کرتے تھے۔ برل مشین پر وہ نظم اگلے دن صبح Dictateکرواتے، میں اس دوران پھر تیار ترجمہ ان کو نثر میں لکھواتا تھا۔ اس طرح سے کوئی تقریباً ایک سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ اس ایک سال میں تقریباً جولائی، اگست ۶۹ء تک کافی کام ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اس دوران اور بھی کتب جو وہ فرمائش کرتے، پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ جو چیزیں انھوں نے نہیں پڑھی تھیں، وہ میں نے پڑھ کر سنائیں۔ ایسے شاعروں، ادیبوں کے نام جو میں نے نہیں سنے تھے، جب ان کی کتابیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں تو اس سے میرا مطالعہ مزیدوسیع ہوگیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میری عربی زبان مضبوط ہو گئی۔ مجھے آج بھی عربی میں لکھنے، بولنے، پڑھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔
جب وہ چلے گئے یہاں سے اپنا کام مکمل کر کے تو ظاہر کہ میرا تعارف یہاں پر سب لوگوں سے ہو گیا تھا۔ پہلے کم تھا، پھر زیادہ ہو گیا کہ یہ عربی، فارسی اچھی جانتے ہیں ۔اس سے لوگوں کا میرے بارے میں تاثر زیادہ اچھا ہو گیا، کیوں کہ عربی جاننے والے اکثر لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ جو یہ کر سکتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، لیکن الحمد للہ میرے اندر یہ تمام صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ اس دوران انسٹی ٹیوٹ میں ملازمت کی آفر ہو گئی۔ انھوں نے مجھے وہاں آفر کی، ہلکا سا انٹر ویو ہوا، مجھے لگا کہ فارمیلٹی ہے۔ کوئی محمدممتاز حسن مرحوم تھے، نیشنل بنک کے ریٹائرڈ صدر تھے اس وقت، ایک دواور حضرات تھے۔ اس طرح ۱۹۶۹ء کی گرمیوں میں، میں نے انسٹی ٹیوٹ جوائن کرلیا۔ اس کے بعد میں انسٹی ٹیوٹ ہی میں رہا۔ اس دوران میں نے پرائیویٹ ایم اے بھی کر لیا تھا اور PhD بھی۔
انیسویں صدی میں مسلمانوں میں جو احیائے اسلام کا کام شروع ہوا، تجدید واحیائے دین کی تحریکیں چلتی رہی ہیں، ان کا بہت معروضی انداز میں مطالعہ کیا جائے تو مختلف لوگوں نے مختلف تحریکات کامطالعہ شروع کیا۔ سنو سی تحریک جو لیبیا میں چلی تھی، یہ آزادی کی تحریک تھی جس کے نتیجہ میں حکومت بھی بنی اور عمرو مختار اسی تحریک کے قائد تھے۔ شاید اس لیے کہ ماخذ کی کمی تھی، جو کام کرنے والے تھے شاید عربی میں اتنے رواں نہ تھے، بہر حال جو بھی وجہ تھی تو میں نے اس پر کام شروع کردیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے سنوسی تحریک کا نام پہلی بار سنا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ لیبیا کے نام سے بھی زیادہ واقف نہیں تھا کہ لیبیا بھی کوئی ملک ہے۔ بہرحال انھوں نے کہا کہ سنوسی تحریک پر کام کریں۔ میں نے تلاش شروع کی اور مواد ملنا شروع ہوا اور میں نے مطالعہ شروع کیا اور ایک کتاب تیار کردی۔ بعد میں کچھ لوگوں کے مشورہ پر اس کتاب یا تحریک کو Reviseکر کے PhD کے مطالعہ کے لیے پیش کردیا۔ اسے یونیورسٹی نے قبول کرلیا اور اس طرح میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان میں غالباً ابھی تک وہ واحد کتاب ہے جو کہ سنوسی تحریک کے بارے میں چھپی ہے۔
میری ابتدائی تعلیم کراچی میں ہوئی۔ میرے والد کا تعلق دہلی کی ایک قریبی جگہ سے تھا، لیکن تعلیم کے بعد کا بیشتر حصہ علی گڑھ یا دہلی میں گزارا ۔علی گڑھ رہے۔ میرے خاندان کا علی گڑھ سے پرانا تعلق تھا۔ میرے دادا علی گڑھ سے پڑھ چکے تھے۔ علی گڑھ کی فٹ بال کی ٹیم کے کپتان تھے۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی جب وہاں جاتے تو ہاتھی ان کو لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ گاڑی تو ہوتی نہیں تھی اور ہاتھی کسی کو لینے کے لیے آئے تو یہ ایک دیہاتی کے لیے نئی بات ہوتی تھی۔ میری دادی کے ماموں جو تھے، بدر الحسن ان کا نام تھا، وہ سرسید کے ساتھ علی گڑھ کالج کے ٹرسٹی تھے۔ بدر باغ ان کے نام سے تھا۔ علی گڑھ اور دیوبند دونوں سے میر اخاندانی تعلق تھا۔ خاندان کے کچھ لوگ دیوبند سے پڑھے تھے، کچھ علی گڑھ سے پڑھے تھے۔ دونوں طرف رجحان تھا۔ یہ بھی ہوا کہ ایک بھائی کی تعلیم علی گڑھ، دوسرے کی دیوبند میں ہوئی، باپ کی دیوبند یا بیٹے کی علی گڑھ میں۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے یعنی دینی اور دنیاوی تعلیم۔ میرے والدصاحب کی تعلیم پہلے مدرسہ میں ہوئی، بعد میں علی گڑھ چلے گئے ۔علی گڑھ سے پڑھنے کے بعد دہلی آگئے اور پرائیویٹ تعلیمی ادارہ قائم کیا جس میں درس وتدریس ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ایک فتح پوری کالج تھا جو اب بھی ہے ،اس میں پڑھایا کرتے تھے۔فتح پوری کالج شایدکامیاب طور پر چلا نہیں، اس لیے والد صاحب نے بعد میں وہ ادارہ چھوڑ کر گورنمنٹ سروس اختیار کرلی۔ سروس میں دہلی میں رہتے رہے۔
جب پاکستان قائم ہوا تو بڑے پر جوش مسلم لیگی تھے، انھوں نے پاکستان کو Opt کیا۔ سرکاری ملازم ہوئے، بہت کام کیا۔ آرڈر ملا کہ۱۷؍اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستانی ہائی کمیشن دہلی میں رپورٹ کریں اور ان کی پوسٹنگ دہلی میں ہوئی۔ ۱۷؍اگست ۱۹۴۷ء کو دہلی میں کرفیو تھا۔ بہت قتل عام ہوا تھا۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ صبح پاکستان کی سروس جوائن کرنی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے رویا کرتے تھے کہ میں صبح آٹھ بجے کپڑے بدل کر روانہ ہو گیا، اب وہاں لوگوں کی لاشیں پھلانگتا ہوا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل اور تلاش کے بعد عمارت ملی جس میں ہائی کمیشن قائم ہوا تھا۔ کافی دیر تک دستک دیتے رہے، کسی نے نہیں کھولا۔ اندر سے کسی نے جھانکا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ میرے پاس لیٹر ہے اورمیں نے جوائن کرنا ہے تو انھوں نے کہا کہ اس حالت میں کیا پاگل ہو؟ واپس جاؤ، دوبارہ آنا۔ پھر ۱۵ کو گئے۔ ۱۷؍ اگست کو امن ہوا تو انھوں نے جوائن کیا اور دہلی میں گئے۔
میری پیدائش دہلی میں ہوئی۔ میں ۴، ۵ سال کا تھا جب دہلی سے پاکستان آیا۔ بچپن میں پرانے مسلمانوں کے قصے کہانیاں پڑھا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری دادی بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔ ان کی تعلیم تو کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن بڑی وسیع المطالعہ خاتون تھیں۔ اردو، فارسی ان کو اچھی آتی تھی۔ اردو کی کتابیں ان کے پاس بہت تھیں۔ وہ اپنے ساتھ کچھ اور تو نہیں لاسکی تھیں، لیکن اپنے مطالعہ کی کتابیں دوصندوقوں میں بھر کر لائی تھیں۔ وہ کتابیں میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک کتاب ان کو زبانی یاد تھی جس کا نام تھا’’ صمصام الاسلام‘‘۔ اس کے لغوی معنی ہیں ’’اسلام کی تلوار‘‘ لیکن یہ ایک منظوم ترجمہ تھا ایک پرانی کتاب کا جو اس نام سے مشہور ہے۔ اس میں شام کے علاقہ میں جو مسلمانوں کی فتوحات کے واقعات تھے ،خالد بن ولیدؓ کی بہادری کے قصے تھے، ابوعبیدہؓ کی بہادری کے واقعات تھے، یہ کسی نے نظم کیے ہوئے تھے۔ یہ میری دادی کو زبانی یاد تھی۔ اس کی بہت سی نظمیں اور شعرمجھے سنایا کرتی تھیں۔ اس سے مجھے یہ واقعات یاد ہو گئے۔ تو ایسی کتابیں جن میں اس طرح کے واقعات ہوں، وہ مجھے اب بھی اچھی لگتی ہیں۔
میں کراچی میں قرآن پاک حفظ کرچکا تھا۔ یہ غالباً ۱۹۵۷ء کی بات ہے، میرے والد کے ایک قریبی دوست تھے۔ میرے والد سے ان کابڑا وسیع تعلق تھا۔ کافی لمبی عمر کے بزرگ تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی کے بھتیجے تھے۔ کراچی میں مولانا اشرف علی تھانوی کی کتابوں کی طباعت کا کام انھوں نے شروع کررکھا تھا ادارہ تالیفات اشرفیہ کے نام سے۔ مولانا کے ملفوظات کی چھ، آٹھ جلدیں انھوں نے شائع کیں جو پروف ریڈنگ کرنے کے لیے میرے پاس آئی تھیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر پروف پڑھا کرتا تھا۔ وہ مسودے کو پڑھتے اور میں اصل کو پڑھتا تھا اور جو غلطی ہوتی، میں ٹھیک کردیتا اور جہاں جہاں قرآن پاک کے حوالے ہوتے تھے، میں حافظ ہونے کی وجہ سے حوالہ نکال دیا کرتا تھا۔ اس کا ترجمہ اور ریفرنس مکمل طور پر وہ دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے بچپن میں، جب کہ اردو نئی پڑھنی سیکھی تھی تو مولانا اشرف علی تھانوی کی کتابیں میں نے پڑھ ڈالیں جب کہ وہ ابھی انھیں چھپوا رہے تھے۔ ویسے تو ملفوظات میں تصوف کے مباحث بہت ہیں۔ اکثر جو فنی چیزیں ہیں، وہ تو میری سمجھ میں بہت کم آتی تھیں، لیکن اس میں جو حکایتیں اورشعروشاعری ہوتی، دلچسپی کی ہوتی تھیں، ان سے مجھے دلچسپی ہو گئی تو اس طرح حضرت تھانوی کی کتابیں بہت بچپن میں پڑھ ڈالی تھیں۔ ان کے پڑھنے سے بہت سارے دین کے اہم حقائق اور اہم چیزیں جو تھیں، وہ ذہن نشین ہو گئیں اور اس طرح بہت ساری ایسی مشکلات سے بچا رہا جس کا بہت سے لوگ شکار ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو ان کا Back Ground معلوم نہیں ہوتا۔
اس دوران کراچی ہی میں تھا کہ اتفاق سے مجھے مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک بزرگ تھے مفتی محمد اکمل جن کے پاس مولانا مودودی ؒ کی کتابیں تھیں تو میں فارغ وقت میں ان کے کتب خانہ میں جایا کرتا تھا اور کتابیں پڑھتا اور دیکھتا رہتا۔ میرا کتابوں کا ذوق انھوں نے دیکھا تو ایک دن کہنے لگے کہ کونے میں جو کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں جو تمھارے کام کی کتابیں ہوں، وہ لے جاؤ تو میں بڑا خوش ہوا اور ایک تخت کے نیچے گھس کر مٹی میں ۲، ۴ دن کتابوں کو چھانٹتا رہا۔ ساری کتابیں باہر نکالیں اور ۵۰، ۱۰۰ کتابوں کا ایک بنڈل باندھا کہ لے جاؤں؟ توانھوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ تو وہ ساری کتابیں میں گھر لے آیا۔ اس طرح میری پہلی Personal لائبریری ان ردی کی عطیہ شدہ کتابوں سے بنی۔ کچھ کام کی نہیں تھیں، لیکن کچھ بہت مفید نکلیں۔ جو اچھی کتابیں تھیں، ان میں دو کتابچے تھے۔ ایک مولانا مودودیؒ کا تھا: ’’پاکستان میں اسلامی نظام اور نفاذ کی عملی تدابیر‘‘۔ یہ لیکچر یا تقریر تھی۔ میں بہت متاثر ہوا کہ یہ بڑے کام کی تقریر ہے۔ مولانا کی کتابیں پڑھنے کا ذوق بھی اس طرح ہوا۔ مولانا کی کتابیں میں نے اس وقت پڑھنی شروع کیں۔ دوسری چیز جو مجھے ان کتابوں میں ملی، وہ ایک قرارداد تھی جو مسلمانوں کے مختلف مسائل کے بارے میں تھی۔ اب یاد نہیں کہ کس ادارے کی تھی، شاید کراچی میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی جو مسئلہ فلسطین اور الجزائر اور دیگر آزادی کی ان تحریکوں کے بارے میں تھی جسے پڑھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ اچھا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ صرف قراردادیں پاس کررہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اور میرے دل میں یہ آیا کہ حکومت پاکستان وہاں پر فوجیں بھیجتی۔ اس طرح کے جذبات میرے دل میں آتے تھے۔ یہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ریزولیشن پاس کرنے کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ لیکن بہر حال اس سے مجھ میں دنیائے اسلام کے معاملات میں دلچسپی لینے کا ذوق پیدا ہوگیا۔ اس دن سے مجھے عالم اسلام کے مسائل سے دلچسپی پید اہو گئی اور اب کافی مسائل سے واقفیت ہے۔
شاعری سے مجھے زیادہ دلچسپی شروع سے نہیں تھی اور شعروشاعری میری طبیعت کے خلاف تھی۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا دل شعر و شاعری میں لگتا نہیں تھا۔ شاید اس وجہ سے کہ میری والدہ مجھے فارسی شاعری پڑھانا چاہتی تھیں جو کہ شاید اس وقت میرے ذوق اور سطح سے بلند ہو گی اور شاید اس وجہ سے شاعری سے میرا دل کھٹا ہو گیا۔ بہر حال جو بھی وجہ ہوگی، لیکن اردو ناول اور افسانے میں میرا دل لگنے لگا۔ اس زمانے میں نسیم حجازی کے میں نے کافی ناول پڑھے۔ ایک خاتون ہوتی تھیں، غالباً اے آر خاتون، بہت اچھا لکھتی تھیں۔ ان کے ناول بھی پڑھے۔ یہ دو نام مجھے یاد ہیں۔ ممکن ہے کہ میری اردو پر اس افسانوی ادب کے پڑھنے کا اثر ہوا ہو۔ اردو میں نے باقاعدہ نہیں پڑھی یا باقاعدہ اردو تعلیم کسی ادارے میں نہیں پائی۔ اردو میں لکھ لیتا ہوں، تحریریں موجود ہیں۔
جب میری دینی تعلیم مکمل ہو گئی تو زیادہ تر عربی مطالعہ کا موقع ملا۔ انگریزی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ انگریزی میں جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رہی، یا تو قانون کے متعلق موضوعات تھے کیونکہ میں فقہ کا طالب علم تھا اور وہ اس لیے کہ اس کے ذریعے قانون کو سمجھنے میں مدد ملتی تھی۔ قانون کی خاص کتابیں پڑھیں اور پھر کچھ قانون کا باقاعدہ طالب علم بھی رہا۔ FEL بھی کیا اور ایل ایل بی کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس میں دو پرچوں میں شرکت نہ کرسکا اور پرچوں میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہو گیا۔ میں نے کوشش کی دوبارہ کرنے کی، لیکن نہیں کر سکا وقت نہ ملنے کی وجہ سے۔ شاید یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ میں وکالت نہ کروں، استادبنوں۔ ۷۳ء، ۷۴ء، ۷۵ء میں قانون پڑھنے کا موقع ملا۔ انگریزی پڑھنے کا ذوق تو موجود تھا۔ میرے دادا علی گڑھ میں پڑھتے تھے ، میرے والدنے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور انگریزی بھی جانتے تھے اور میرے خاندان میں کافی لوگ دینی ودنیوی تعلیم کے حامل موجود تھے۔ بچپن کراچی میں ہی گزارا اور پھر اسلام آباد کا ماحول انگریزی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ انگریزی پڑھنے کی کوشش کی، میری کوشش تھی کہ ایسی کتابیں پڑھوں جو مغربی تصورات کو سمجھنے میں مدد دیں۔ اس کا احساس علامہ اقبال کی شاعری کے مطالعے سے ہوا۔
علامہ اقبال کے کلام کے مطالعہ کا ذوق کب پیدا ہوا؟ یہ کہنا مشکل ہے لیکن ۱۹۶۵، ۶۶ء کے لگ بھگ ہوا۔ اس سے پہلے اقبال کی کوئی خاص چیز نہیں پڑھی تھی اور پھر اتنا ہوا کہ دو تین سال ایسے گزرے کہ میں نے علامہ اقبال کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں اور اس زمانے میں مجھے کلام اقبال تقریباً سارا یاد تھا اور اب چالیس بیالیس سال ہو گئے ہیں، اب بھی آپ کوئی شعر مجھ سے پوچھ لیں تو تقریباً ۹۰ فیصد شعر کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ فلاں غزل میں فلاں کتاب کا حصہ ہے۔ ۹۰ فیصد شعر تو اب بھی مجھے یاد ہیں۔ مجھے کلام اقبال کو بیان کرنے میں کبھی دقت نہیں ہوئی۔ اسی عرصے میں شیخ شعلان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو کلامِ اقبال کے مطالعے سے یہ ذوق پیدا ہوا کہ مغرب کا تنقیدی مطالعہ ضروری ہے اور مغربی افکار سے واقفیت کے بغیر اور اس کے بارے میں ایک موقف اختیار کیے بغیر دور جدید میں مسلمانوں کا احیاناممکن ہے۔ اس کا جب احساس ہوا تو میں نے مغربی افکار کا مطالعہ شروع کیا۔ میری دلچسپی کے جو میدان تھے، وہ قانون، دستور اور کسی حد تک معیشت تھے، اگرچہ یہ میرا اتنا پسندیدہ موضوع نہیں رہا، لیکن سیاست کو سمجھنے کے لیے معیشت کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور تھوڑا سا مغربی افکار کی تاریخ اور مغربی تہذیب کا پس منظر، مذہب اور ریاستی کشمکش، یہ چیزیں میری دلچسپی کا موضوع رہی ہیں۔ اس پر میں نے کچھ کتابیں پڑھیں، لیکن جس کتاب سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، وہ ول ڈیورنٹ کی کتاب The Story of Civilization ہے جو آٹھ جلدوں میں ہے۔ یہ کتاب میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے اورنہایت باریک بینی اورگہرائی سے پڑھی ہے۔ ایک تو اس سے انگریزی بہتر ہو جاتی ہے اور ویسے بھی ان چیزوں کے متعلق جن کے بارے میں ذہن میں سوالات پیدا ہوتے تھے، ان کا جواب اس کتاب میں تھا۔Will Durant کی اس کتاب کے علاوہ مغربی افکار اور مغربی تہذیب کو جاننے کے لیے میں نے جو کتابیں دیکھیں، ان میں ٹرینڈ رسل کی کتابیں بہت اہم ہیں جو کہ میں نے پڑھی ہیں۔ اس کی کتابوں میںHistory of Western Philosophyجیسی کتاب کو میں نے تین چار مرتبہ پڑھا ہے۔ اس سے مغربی افکار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کس دور میں کیا تھا اور مغرب میں کس دور میں کیا خیالات پیدا ہوئے، اس کا پس منظر کیا تھا۔ ان کتابوں کو پڑھنے سے مغربی افکار اور تہذیب کو سمجھنے میں مدد ملی۔ مغرب کو جاننے میں ایک اور کتاب جس سے بڑی مدد ملی ہے، میں نے اسے پاکستان کونسل کی لائبریری سے لے کر پڑھا۔ گبن کی کتاب The Fall of Roman Empire اگرچہ پرانی ہے، Outdated ہے، لیکن کتاب بہت اچھی ہے۔ اس سے مغربی رومن امپائر اورر ومن چرچ اور ان چیزوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی۔ یہ چیزیں جب تھوڑی سی پڑھ لیں تو اقبال کی شاعری میں مجھے بہت گہرائی ملی۔ علامہ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ جتنا آدمی گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی سطح پر ہے۔
اسلامی قانون پر تو بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے چند کا ذکر کروں گا۔ مغربی قانون کے بارے میں دو کتابیں مجھے بڑی پسندآئیں جنھیں میں کثرت سے پڑھتا ہوں۔ اے کے بروہی صاحب کی کتاب ہےThe Fundamental Law of Paksitan۔ اصل میں تو یہ ۱۹۵۶ء کے Constitution کی شرح ہے، لیکن انھوں نے مغربی قوانین کے تصورات، شہری اور تمام وہ بنیادی عقائد جس پر مغربی قوانین کی اساس ہے، ان پر بحث کی ہے۔ اتنی عالمانہ بحث بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ یہ کتاب مجھے بہت پسندآئی اور اسے میں نے کئی مرتبہ پڑھا اور اب بھی ہمیشہ اسے وقتاً فوقتاًدیکھتا رہتا ہوں اور میرے خیال میں کسی اور مسلمان کی اس موضوع پراتنی جامع کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ Jurisdictionپر ایک اور کتاب پڑھی جو نئے انداز سے لکھی گئی ہے۔ اس کے مصنف نے ایسا التزام کیا ہے کہ اس میں تمام بنیادی تصورات دینے والے ماہرین قانون ہیں۔ مغربی دنیا کے اہل علم کے تصورات کے اقتباسات پیش کر کے اور بنیادی قانونی تصورات پر بحث کی ہے۔ یہ بھی مجھے بڑی پسندآئی۔ سترہویں اٹھارویں صدی میں جب سے اس پر غور شروع ہوا ہے کہ کس نے کیا لکھا ہے، Montersنے کیا لکھا تھا اور Kalsenنے کیا لکھا تھا، Rousseau نے کیا لکھا تھا تو گویا قانون تصورات کی تاریخ بھی آگئی۔ Rousseau کی اپنی زبان میں اس کا بیان بھی آگیا کہ انہوں نے Social Contractکے بارے میں کیا لکھا تھا، اس میں قانون دانوں کے اپنے دلچسپی کے موضوعات بھی ہیں۔
مجموعی طور پراسلامیات سے متعلق چیزیں ہی میری دلچسپی سے متعلق ہیں۔ اسلامی تاریخ و تمدن، تصوف اور اس طرح کی ہر چیز جیسے سید علی ہجویریؒ ]کی تحریریں[، مجدد الف ثانی کے مکتوبات۔ مجدد الف ثانی کے جو مکتوبات ہیں، وہ تصوف کی بنیاد ہیں اور تصوف میں اس سے زیادہ ٹھوس اور جامع تحریر کسی کی بھی نہیں ہے۔ پورے ۱۴۰۰ برس میں کسی بھی مسلمان صوفی کی اتنی جامع اور ٹھوس تحریریں نہیں ہیں جتنی کہ مجدد الف ثانی کی تحریریں ہیں۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہGreatest Muslim Genius of India، یہ میں نے سارے پڑھے ہیں۔ اس میں سے ۱۱۰۰ کے قریب منتخب مکتوبات کا عربی ترجمہ بھی کیا ۔شاہ ولی اللہ کی کتب پڑھیں۔ امام غزالیؒ کی’’ احیاء العلوم‘‘ تو ہمیشہ میرے سرہانے رہتی ہے جس کو وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہوں۔ مولانا تھانوی کی کتب بچپن میں ہی پڑھ لی تھیں۔ بنیادی چیزیں پڑھیں۔ عصر جدید کے تمام لوگوں کو پڑھا، لیکن بنیادی جو کتابیں ہیں، وہ قوت القلوب ہے ابوطالب مکی کی، کتاب اللمعہ، رسالہ قشیر یہ ہے۔ یہ سب الحمدللہ میرے پاس ہیں۔ دورِحاضر کے مصنفین میں تصوف پرٹھوس اصل کام کسی نے بھی نہیں کیا ہے، یعنی ایسا تو ہے کہ کچھ لوگوں نے تصوف کو نئے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ان میں دو تین کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ایک تو مولانا زوارحسین صاحب جو کہ کراچی کے ایک بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے ’’عمدۃ السلوک‘‘۔ ایک مولانا اللہ یار خان تھے یہاں چکوال کے قریب، ان کی کتاب ہے ’’دلائل السلوک‘‘۔ یہ دونوں اچھی کتابیں ہیں، لیکن میرے ذہن میں اس سے مختلف نقشہ ہے۔ ایک بزرگ میرے دوست ہیں، صاحبزادہ محمد حسن الٰہی، یہاں قریب ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ وہ بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ عالم فاضل ہیں، استاد بھی ہیں، ان کی تحریریں بھی تصوف پر اچھی تحریریں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے گزارش کی ہے کہ ان سب کو مرتب کر کے تصوف پر ایک جامع کتاب تیار کریں جس میں ان اعتراضات کا جواب بھی موجود ہو جو کہ عموماً تصوف پر کیے جاتے ہیں۔ بڑے وزنی اعتراضات ہیں، ہلکے اعتراضات نہیں ہیں اور جو تصوف کے علم برداران کہتے رہے ہیں، وہ بھی بڑا وزنی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے اہم اور عظیم ترین لوگ تصوف کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اس لیے آپ اسے آسانی سے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ بیک جنبش قلم کہہ دیں کہ تصوف فضول ہے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ٹھوس مطالعہ کی ضرورت ہے۔
اسی طرح عصر حاضر میں مولانا مودودیؒ کی اکثر معروف کتب پڑھی ہیں۔ میں مولانا کی دو کتابوں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اب بھی دوبارہ پڑھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا تاثر بالکل صحیح تھا۔ جو کتابیں مولانا کی بہت مقبول ہیں اور جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، میں ان سے متاثر نہیں ہوا۔یہ دو کتابیں ’’تنقیحات‘‘ اور ’’اسلام اور جدید معاشی نظریات‘‘ ہیں۔ یہ کتابیں مجھے بہت غیر معمولی فاضلانہ اور Creativeمحسوس ہوئیں۔ مولانا کی جن کتابوں سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، ’’خلافت وملوکیت‘‘ اور ’’قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں‘‘، ’’تجدید واحیائے دین‘‘ ہیں۔ ان کتابوں نے مجھے بہت کم متاثر کیا۔ مولانا کا احترام مانع ہے، ورنہ اس بات کو اور پھیلا سکتا ہوں۔ یہ مجھے مولانا کے معیار کی کتابیں معلوم نہیں ہوئیں، جو مولانا کا علمی معیار ہے۔ ’’خلافت و ملوکیت‘‘ کے بارے میں ایک اچھی کتاب حافظ صلاح الدین یوسف کی ہے جوبڑی معتدل اور اچھی کتاب ہے۔
اصل میں، میں مولانا پر وہ اعتراضات نہیں کرتا جس طرح کے اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں اور میں اُس طرح کے خیالات کے اظہار میں مولانا کو معذور اور کسی حد تک حق بجانب سمجھتا ہوں۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بڑا فاضل مفکر اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ظاہر ہے کہ اگرماحول کا نوٹس (Notice) نہ لے تو وہ بڑا مفکر نہیں بن سکتا۔ وہ کیا مفکر ہے کہ جو ماحول کا جواب نہ دے اور نہ ہی بالکل ماحول کا اسیر ہو جائے۔ تو ہر مفکر کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اُس میں اتنی عالمگیریت ہو کہ ماحول سے بہت آگے جا کر بات کرے، لیکن اُس کے ساتھ ماحول کا نوٹس لے کر اُس کا جواب بھی دے۔ تو مولانا جس ماحول میں لکھ رہے تھے، وہ مسلمانوں کی انتہائی پستی کا دور تھا۔ کوئی ایسی قابل ذکر قوت نہ تھی جو مسلمانوں کے مقاصد کو لے کر چل سکے، جو مسلمانوں کی مصلحت اور Cause کا تحفظ کر سکے۔ اُس کے مقابلے میں Communism کی ایک بڑی قوت قائم ہو گئی تھی جو Communism کو ایک پوری دنیا میں فروغ دے رہی تھی، وسائل استعمال کر رہی تھی۔ برطانیہ کی بڑی قوت تھی جو پوری دنیا میں اپنے وسائل سے انگریزی زبان، انگریزی کلچر اور انگریزی اقدار کو فروغ دے رہی تھی۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے انگریزی اقدار کو فروغ دینے کے لیے قائم کیے جا رہے تھے۔ تو اگر مولانا مودودی کے ذہن میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی بھی ایک ریاست اُسی طرح کی ہونی چاہیے تویہ ان کی ذات میں موجود اخلاص کی بات ہے۔ اِس درد مندی اور اخلاص سے انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا ہو گا تو اُن کو لگا ہو گا کہ بڑی بڑی حکومتیں اپنے تصورات کو پھیلا رہی ہیں جو اسلام کے نقطہ نظر سے غلط ہے تو اگر اسلام کی بھی اس طرح کی ایک سلطنت ہو جو اُس Cause کو لے کر چلے تو اسلام کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اِس لیے مولانا نے اُس کے لیے قوم کو آمادہ کرنا شروع کیا۔ اِس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکل سکتا تھا کہ مولانا کے اندازِ تخاطب اور طرزِ تحریرمیں سیاسیات کا پہلو بہت نمایاں ہو گیا۔ سیاسیات کے پہلو کا نمایاں ہونا اس لیے نہیں کہ مولانا اسلام میں بھی سیاست کو وہ مقام دیتے ہیں جو اُن کی تحریروں سے نظر آتا ہے۔ اُن کی تحریروں میں سیاسیات کی نمایاں حیثیت اِس لیے نظر آئی کہ مولانا جس دور میں لکھ رہے تھے یا جس طبقے سے مخاطب تھے، اُس طبقے کا بڑا مسئلہ یہ تھا۔ اب یہ سمجھنا کہ مولانا اسلام کے عمومی نظام میں سیاست کو بھی وہ درجہ دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مولانا کے ساتھ انصاف نہیں ہے، لیکن اُن کی تحریروں سے یہ رنگ پیدا ہوتا ہے۔ خواہی نخواہی، دانستہ یا نا دانستہ اُس سے قارئین کا ذہن یہ بنا تو پھر اس پر مولانا ابو الحسن علی ندوی کو قلم اٹھانا پڑا۔
مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی کتاب ’’پرانے چراغ‘‘ بہت معیاری کتاب ہے۔ میری شخصیت پر اس کے بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں، البتہ ان کی شہرت کی وجہ جو کتاب ہے، وہ مجھے پسند نہیں آئی۔ ’’انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر‘‘ میں نے پہلے عربی میں پڑھی تھی۔ اس کی زبان بہت اچھی ہے، عربی میں وہ کتاب میں نے enjoy کی، لیکن اس کے مند رجات نے مجھے متاثر نہیں کیا۔ مولانا کی جس کتاب سے بہت متاثر ہوا اور بار بار پڑھی ہیں، وہ ’’پرانے چراغ‘‘ اور ’’سیرت سید احمد شہیدؒ ‘‘ ہیں۔
میں ایک زمانے میں کمیونزم سے بڑا متاثر ہوا۔ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں پاکستان کی چین نے بڑی مدد کی تھی اور بڑا چرچا تھا اس کا۔ اس زمانے میں چینی سفارت خانہ کمیونزم پر بڑی کثرت سے لٹریچر تقسیم کیاکرتا تھا۔ تو وہ لٹریچر دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ واقعی اگر دنیا میں کوئی مظلوموں کا ساتھی ہے تو وہ کمیونسٹ ہیں۔ انگریزی میری اتنی رواں نہیں تھی کہ میں انگریزی کی کتابیں پڑھ سکوں۔ عربی میں بھی کوئی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن جو کچھ ملتا تھا، میں نے پڑھنے کی کوشش کی اور کوئی سال سوا سال ایسا گزرا کہ کمیونزم کے بارے میں میری بڑی اچھی رائے رہی اور جو چیزیں اس بارے میں ملیں، میں نے پڑھیں۔ پھر ۱۹۶۶ء کی بات ہے جب انڈونیشیا میں انقلاب آیا۔ وہاں کمیونسٹوں کا قتل عام شروع ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ تو بے گناہ لوگوں میں عدل وانصاف کی بات کرتے ہیں، انسان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب باقی چیزیں پڑھیں اور کچھ سنجیدہ مطالعہ ہوا تو پھرکمیونزم کے بارے میں یہ تاثر ختم ہو گیا اور بعد میں تو بالکل مختلف تاثر بن گیا۔ Communismبالکل فضول ہے اور مذہب بیزار زندگی، غیراخلاقی زندگی۔ ان کے سارے دعوے باطل اور غلط ہیں۔ نہ اس میں مزدور کی فلاح وبہبود ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس نظام نے مزدروں کو مزید غلام بنایا۔ کمیونسٹ حکومتوں نے ان پر مزید مظالم کیے۔ اس بارے میں ایک کتاب جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، وہ پروفیسر مظہر الدین صدیقی کی کتاب تھی۔ ’’اشتراکیت اور نظام اسلام‘‘ اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب کمیونزم پر زیادہ لٹریچر اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے نہیں ملتا تھا۔ غالباً ۱۹۴۰ء کے زمانے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور کتاب تھی’’ اسلام اور مارکسزم‘‘۔
کتابیں لینے اور دینے کے بارے میں تھوڑی سخاوت بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ میری بہت سی کتابیں واپس نہیں آئیں۔ سینکڑوں جو بہت سے احباب لے گئے پڑھنے کے لیے۔ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا اور نہ ہی رجسٹر تھا کہ میں درج کرتا جاتا کہ اس کا اندراج ہو۔ پاکستان کی ایک بڑی نامور شخصیت نے مجھ سے کتاب لی اور پھر صاف مکر گئے اور میں بھی احتراماً خاموش رہا۔
میں دورانِ سفر بھی مطالعہ کرتا ہوں۔ کتابیں سفر میں ساتھ رکھتا ہوں، خاص طور پر ادب کی اور شاعری کی۔ شاعری میں زیادہ فارسی اور عربی شاعری پڑھتا ہوں۔ انگریزی شاعری پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے پسند نہیںآئی۔ میں نے بہت چاہا کہ انگریزی شاعری بھی پڑھوں۔ فارسی شاعری میں قدیم شاعری سے متاثر ہوا ہوں، جبکہ جدید شاعری نے کبھی متاثر نہیں کیا۔ قدیم شاعری میں حافظ، غالب، سعدی اور سنائی۔
اخبار صبح پڑھتا ہوں صرف ناشتے کے دوران۔ جنگ، ڈان اور Pakistan Observer پڑھتا ہوں۔ زاہد ملک صاحب مفت صبح صبح اخبار دیتے ہیں۔ باقی رسائل میں ریگولر نہیں پڑھتا۔ بہت سے حضرات بھیجتے ہیں۔ بس ایک نظر میں دیکھ لیتا ہوں۔ باقاعدہ ضرور نوائے وقت اور جنگ کے کالم پڑھتا ہوں، کیوں کہ بھائی کے گھر میں نوائے وقت آتا ہے۔
عموماً رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہوں۔ کرتا یہ ہوں کہ سال کا ایک پلان کرتا ہوں کہ سال میں یہ پڑھنا ہے تو کتاب پہلے ہی طے کر تا ہوں۔ کتابیں تو دنیا میں لاکھوں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ بیس یا پچیس ہزار کتابیں پڑھ سکتے ہیں زندگی میں یا دس بارہ ہزار پڑھ سکتے ہیں۔ اِن لاکھوں کتابوں میں آپ دس ہزار کتابیں منتخب کرتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں۔
کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہوتا ہے۔ آپ دس، پندرہ منٹ کے لیے نظر ڈال لیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی کتاب ہے، اِن میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بک سیلرکے پاس ہی جا کر دیکھتا ہوں۔ اسلام آباد کے کئی بک سیلر مجھے جانتے ہیں اور دوست ہیں۔ میں شیلف پر کھڑا ہو کر پندرہ منٹ نظر ڈال کرکتاب کا ]حاصل[ اخذ کر کے کتاب فارغ کر دیتا ہوں۔ اُس کے بعدان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن کو مجھے دو گھنٹے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ اُسی کی مستحق ہوتی ہیں کہ آپ دو تین گھنٹے اُس پر لگائیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار پڑھنے کی ہوتی ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں۔ تو جو ایسی کتابیں ہوتی ہیں، وہ میں خریدلیتا ہوں۔ جو ایسی نہیں جن کو وقتاً فوقتاً دیکھنا ہوتا ہے، اُن کو بھی خریدنا پڑتا ہے۔ جو کتابیں گھنٹے اور دو گھنٹے میں فارغ ہوتی ہیں، وہ میں نہیں خریدتا۔ میری ذاتی لائبریری میں کتابیں میں نے کبھی گنی نہیں، مگر میرا اندازہ ہے کہ بیس بائیس ہزار کتابیں ضرورہوں گی۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ملنے کا اشتیاق ہوا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی سے ملنے کی خواہش کی ہو اور ملنے کے بعد مایوسی ہوئی ہو۔ یاد نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو، لیکن کچھ مصنفین جن سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتی رہی لیکن مل نہ سکا، اِن میں سے ایک تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ جب کلام اقبال اوڑھنا بچھونا تھا تو اُن کی شرحیں میں نے ساری پڑھی ہیں۔ نثر میں لکھیں۔ سب پڑھیں تو اُن سے ملنے کا بڑا اِشتیاق رہا۔ تین چار بار لاہور اُن سے ملنے گیا، لیکن اتفاق سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بس ایک مرتبہ اُن کو زندگی میں دیکھا۔ لاہور میں ایک جلسہ تھا۔ یہ غالباً ۱۹۷۶ء کی بات ہے۔ اُس میں ایک میری تقریر تھی۔ اسٹیج پر چار، پانچ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب صدارت کر رہے تھے۔ مولانا کے ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا کے دائیں جانب ایک بوڑھے سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں۔ جب اعلان ہوا کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی تقریر کریں گے تو میں ایک دم چونکا۔ اُن بزرگ نے اٹھ کر تقریر کی۔ میں نے کہا کہ آج میں مل کر ہی جاؤں گا۔ میری بدنصیبی کہ وہ تقریر کر کے کہنے لگے کہ مجھے کام ہے اور وہ چلے گئے۔ اِس کے علاوہ نہ کبھی اُن کو دیکھا نہ اُن سے ملاقات ہوئی۔
باقی جن حضرات سے ملنے کا اشتیاق ہوا اور اُن سے ملاقات ہوئی تو بعض سے بہت استفادہ بھی کیا۔ دو بزرگوں سے تو میں کوشش اور اہتمام سے ملا جن کی کتابیں میں نے پڑھی تھیں اور بعد میں اُن سے بہت نیاز مندی رہی۔ ایک تو کراچی میں رہتے تھے اور جب بھی میں کراچی جایا کرتا تھا، اُن کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، اُن کی تمام کتابیں پڑھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تاریخ نویسی کے فن کی وہ معراج ہیں۔ اُن سے بڑا مورخ برصغیر میں شاید بیسویں صدی میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ برصغیر میں بیسویں صدی میں تاریخ نویسی کا سب سے بڑا نام کون ہے تو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی۔ میں اُن سے ملنے کے لیے گیا۔ میرا خیال تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، وزیر ہیں، اُن سے ملنا مشکل ہو گا۔ اُ ن کے ایک شاگردکی معرفت میں اُن سے ملنے گیا تو وہ ایسے ملے جیسے کوئی باپ یا استاد ملتا ہے تو بڑی حیرت ہوئی۔ اس طرح ملنے کے بعدپہلے جو احترام اور رعب تھا، اب اُس میں محبت بھی شامل ہو گئی تومیں جب بھی جایا کرتا تھا تو ملتا تھا، بہت ہی شفقت سے ملتے، ایسے جیسے ساری عمر سے جانتے ہیں۔
مجھے اشتیاق تھا مصطفی الزرقا سے ملنے کا۔ استاد مصطفی الزرقا شام کے تھے اور جو بات میں نے اشتیاق حسین قریشی کے بارے میں کہی ہے، مصطفی الزرقا کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ بیسویں صدی میں اُن سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا۔ فقہ اسلامی میں گرفت اور گہرائی کے ساتھ کسی کی نظر نہیں تھی جتنی پوری دین اسلام کے بارے میں استاد الزرقاکی تھی، بلکہ مجھے اجازت دی جائے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ علامہ اقبال نے ۱۹۲۵ء میں لکھا تھا کہ جو شخص زمانہ حال کے تمام احکام قرآنیہ کی ابدیت ثابت کرے گا، وہ اسلام کا سب سے بڑا مفسر ہو گا۔ یہ کام جن لوگوں نے کیا ہے بیسویں صدی میں، اُن میں مصطفی الزرقا کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اُنہوں نے بہت غیر معمولی انداز میں کام کیا ۔وہ شام میں رہے اور کچھ عرصہ سعودی عرب میں رہے۔ میری اِن سے پہلی ملاقات ۱۹۷۹ء میں ہوئی۔ اکتوبر ۷۹ء میں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا نفاذ اسلام کے بارے میں تو اُس میں وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اخبار میں آرہا تھا کہ مصطفی الزرقا بھی آئے ہوئے ہیں تو مجھے بڑا اشتیاق تھا۔ اس کی افتتاحی تقریب تھی تو میں اُس میں شرکت کے لیے گیا تو میں ہر ایک کو دیکھتا رہا کہ یہ مصطفی الزرقا ہوں گے، یہ ہوں گے۔ تو ایک صاحب پر نظر پڑی جن کا چہرہ مجھے معصوم سا لگا تو مجھے لگا کہ یہی ہیں مصطفی الزرقا تو میں نے پوچھا کہ آپ مصطفی الزرقا ہیں؟ تو کہنے لگے، ہاں تو اُن سے مل کر طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ وہ مجھ پربڑے مہربان ہوئے۔ اتنے مہربان ہو گئے کہ میری حیثیت سے بڑھ کر میرے بارے میں رائے قائم کرنے لگے۔ خط وکتابت اِن سے ہوتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اُن کا خط میرے نام آیا تو میں نے شرم سے چھپا لیا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے اور دیکھے گا کہ تو کیا کہے گا یعنی لوگ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جعلی عکس ڈال رکھا ہے، اُن پر غلط بیانی کر رکھی ہے اپنے بارے میں، اس لیے وہ ایسی بات لکھتے ہیں۔
ایک اور بزرگ جن سے بڑا ملنے کا اشتیاق رہا، اُن سے ملاقات بھی رہی اور بہت مہربان بھی رہے، وہ تھے مولانا صباح الدین عبد الرحمن۔ یہ ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ اِن کی برصغیر کی تاریخ پر کئی زبردست کتابیں ہیں اور اردو زبان بڑی ہی نفیس لکھتے اور بولتے تھے۔ بہت ہی سادہ اور نفیس انسان تھے۔ اگر کسی نفیس انسان کی نفسیات کے ۱۰۰ نمبر ہوں تو ۹۹ نمبر اُن کو دوں گا۔ یہ دارالمصنفین کے ناظم تھے۔ کتابیں میں نے اُن کی پڑھی ہوئی تھیں۔ تو ایک دفعہ انسٹی ٹیوٹ میں، میں صبح صبح پہنچا تو گرمی کا زمانہ تھا۔ یہ ۱۹۷۵ کی بات ہے۔ میں دفتر میں پہنچا تو ایک صاحب نے کہا کہ آئیے، آپ کو ایک بزرگ سے ملاتے ہیں۔ تو انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ڈائریکٹر کے کمرے میں لے گئے۔ وہاں ایک صاحب شیروانی اورپاجامہ پہنے ہوئے، جیسے ہندوستان کے لوگ پہنتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن سے تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ صباح الدین عبد الرحمن ہیں۔ میرے ذہن میں اُن کا جو نقشہ تھا، وہ بالکل اُس سے مختلف نکلے۔ اُس کے بعد مجھ پر اتنے مہربان ہوئے کہ پھر اُن کی زندگی کے آخری ایام تک اُن سے بڑا تعلق رہا۔ میں اُن سے ملنے کے لیے ہندوستان بھی گیا۔ وہ جب بھی آتے تو میرے پاس تشریف لاتے تھے۔ ان کی کتابوں میں بزم صوفیہ، بزم تیموریہ اور’’ ہندوستان میں مسلمانوں کے جلوے‘‘ اور ہندوستان میں مسلمانوں کا عسکری نظام، تمدنی نظام،’’ ]شامل ہیں[۔ ’’بزم صوفیہ‘‘ میں ہندوستان کے بڑے صوفیہ کا تذکرہ ہے، داتا گنج بخش سے لے کر خواجہ بہاء الدین نقشبند وغیرہ تک بلکہ خواجہ نظام الدین اولیا تک۔ ’’بزم تیمور یہ‘‘ مغل سلطنت کے زمانے کے تمدنی اور تہذیبی اور ثقافتی معاملات پر ہے۔ ’’بزم مملوکیہ‘‘ مغل دور سے پہلے کے تمدنی دور پر ہے۔
بھائی جان
ڈاکٹر محمد الغزالی
(۱۹ دسمبر ۲۰۱۱ء کو رابطۃ الادب الاسلامی پاکستان کے زیر اہتمام جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں ڈاکٹر محمود احمد غازی کی یاد میں منعقدہ سیمینار میں خطاب۔)
الحمد للہ رب العالمین والصلوۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔
واقعہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات بھائی جان کو مجھ سے شاید زیادہ ہی جانتے ہوں گے۔ میں بطور بھائی کے یقیناًنسبی رشتہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے آپ حضرات کی گفتگو سن کر بہت رشک آیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی صاحب کی کوششیں جو وہ بہت خاموشی سے کرتے رہتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، الحمد للہ اس قدر اس کی بازگشت ہے، اہل علم کے ہاں اعتراف ہے اور طلبہ اور تشنگان علم کے ہاں اس کی پوری قدر ہے۔ ابھی میرے چچا مولانا اسعد تھانوی صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ والد مرحوم نے بہت عزیمت کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرائیں گے اور دینی تعلیم سے ان کوبہرہ مند کریں گے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے جس سے اس بات کی مزید توضیح اور تاکید ہوتی ہے جو میرے چچا صاحب نے بیان فرمائی۔
بچپن کا واقعہ ہے ۔ بھائی صاحب کو بہت ابتدائی عمر میں کوئی بخار ہوا تھا جس کی کوئی بہت سخت دوا کسی ڈاکٹر نے دی تھی تو ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی ۔ جب وہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت ان کی زبان میں اچھی خاصی لکنت تھی۔ رفتہ رفتہ وہ لکنت کم ہو گئی، شاید بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو کہ تھوڑی بہت اخیر تک رہی۔ آخر میں انھوں نے بڑی حد تک اس پر قابو پا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکتبوں میں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں، وہ کس قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔ کراچی میں جس کے پاس ان کو بٹھایا، اس نے یہ سوچے بغیر کہ ایک بچے پر نفسیاتی طور پر کتنا برا اثر ہوتا ہے، کہہ دیا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو اٹھا لیجیے۔ والد صاحب گئے، اس سے ملے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیوں حفظ نہیں کر سکتا؟ انھوں نے کہا کہ یہ اٹکتا ہے، اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہی نہیں۔ اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ نہیں حفظ کر سکتا۔ والد صاحب مرحوم نے کہا کہ اچھا بیس برس میں تو کر لے گا نا؟ اب وہ کیا کہتا کہ بیس برس میں بھی نہیں کرے گا! خاموش ہوگیا۔ والد صاحب نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ یہ کچھ نہ کرے، قرآن حفظ کر لے، مجھے منظور ہے۔ اتنا یقین تھا ان کا اور یہ یقین ایک ایسے شخص کا تھا جو دن رات ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا جو نہ صر ف یہ کہ ایک دوسرے رنگ کے تھے بلکہ ہمارے والد اور والدہ کو طعن وتشنیع کرنے والے بھی بہت ملتے تھے۔ ایسے کلمات بھی سننے کو ملتے تھے کہ اگر آپ کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کیوں ان کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ مگر ہمارے والدین نے کبھی کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ نہ دفاع کیا، نہ وضاحت کی، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب کے اندر کچھ خدادا دا ملکہ اور صلاحیت عجیب وغریب تھی اور بہت ذوق وشوق تھا پڑھنے کا۔ مجھے یاد نہیں ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں کہ کبھی بچپن میں بھی انھوں نے کھیل کھلونے میں کوئی دلچسپی لی ہو۔ ہمارے والد کہیں سفر پر جاتے تھے تو وہ ان سے کتاب ہی کی فرمائش کرتے تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ انھوں نے کبھی کوئی کھلونا یا بچپن یا لڑکپن میں جن چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اس کا کبھی مطالبہ کیا ہو۔ ویسے وہ مطالبہ ہی بہت کم کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی ایک عجیب وغریب بات تھی کہ بہت بے نیاز تھے۔ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ والدین سے بھی اپنی کوئی ذاتی خواہش یا فرمائش کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ حضرات جو واقف ہیں، وہ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ اگر کبھی والد صاحب نے اصرار کیا کہ ہاں بتاؤ، تمھارے لیے کیا لاؤں تو کوئی کتاب بتا دی۔ کتاب سے بہت زیادہ دلچسپی اور علم کا حصول ان کی اولین priority تھی۔ کوئی ambition نہیں تھی، دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی۔
کراچی میں ہم جیکب لائن سے بنوری ٹاؤن پڑھنے جاتے تھے۔ فاصلہ غالباً چار پانچ کلومیٹر ہوگا تو وہ اکثر مجھے ورغلا کر لے جاتے تھے کہ ہم پیدل چلیں گے۔ راستے میں قائد اعظم کا مزار آئے گا اور پھر وہاں سے مدرسے چلیں گے ۔ وہ اس میں کچھ تفریح کا رنگ پیدا کرتے اور میں ان کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ پیسے بچا کر کتابیں خریدتے ہیں۔ اس طرح ’’سازشیں‘‘ کر کے انھوں نے بچپن سے کتابیں جمع کیں اور کیا کسی عورت کو زیور سے دلچسپی ہوگی اور کسی اور شخص کو اپنی پسندیدہ چیز سے جو انھیں کتاب سے تھی۔ اخیر عمر تک کتابیں سنبھال سنبھال کر رکھتے رہے، یہاں تک کہ گھر میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ بیڈ روم میں کتابیں، لاؤنج میں کتابیں، ڈرائنگ روم میں کتابیں، ڈائننگ روم میں کتابیں ہی کتابیں۔ تو جب کوئی شخص علم کی طلب ایسی رکھتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بھی اس پر فضل ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دعویٰ تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم علم دوست ہیں، کتاب دوست ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری دل کی خواہش جس کو کہتے ہیں: ہوی الاحبۃ منہ فی سوداءہ، وہ نہیں ہوتی۔ جب وہ ہو جائے تو پھر عطا ہوتی ہے۔ کلا نمد ہولاء وہولاء، اللہ تعالی کا اصول ہے۔ جو چیز جو طلب کرتا ہے، ضرور ملتی ہے۔جتنی طلب کرتا ہے، اتنی ملتی ہے۔
دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر
تو بھائی صاحب میں غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہوئیں، حالانکہ ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو چار سال انھوں نے بنوری ٹاؤن میں پڑھا، اس کے بعد دار الحکومت منتقل ہوا تو ہم لوگ اسلام آباد آ گئے۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا قاری محمد امین صاحب کا۔ وہ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے او رمسجد فتح پوری دہلی میں جومشہور مدرسہ ہے، وہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا یوسف بنوری صاحب مرحوم نے ایک ذاتی خط لکھا تھا کہ یہ دو بچے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا اور ان کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیجیے گا تو وہاں ہم کچھ دن رہے۔ وہاں قاری امین صاحب ہی ایک کام کے آدمی تھے، باقی وہ مدرسہ ایسا ہی تھا۔ پھر ہم مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ ان کے نام مولانا احتشام الحق تھانوی نے خط لکھ دیا تھا کہ ان کا خیال رکھیے گا اور انھوں نے واقعی بہت خیال رکھا۔ان کے ہاں دورۂ حدیث پشتو میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بہت مشہور حدیث کے عالم تھے، مولانا عبد الرحمن۔ان کے بھائی تھے، مولانا عبد الحنان۔ دونوں سوات کے کسی دیہات کے رہنے والے تھے۔ غیر معروف تھے، لیکن فنا فی الحدیث اور بہت عالم فاضل شخصیت تھے۔ بہت سے لوگ افغانستان میں ان کے معتقد تھے۔ اکثریت چونکہ پشتون لوگوں کی تھی تو دورۂ حدیث پشتو میں ہوتا تھا۔ بھائی صاحب کا جب نمبر آیا تو ان کو ایک اور ملکہ یہ تھا کہ مسئلہ یوں چٹکیوں میں حل کرتے تھے۔ جو مسئلہ بہت مشکل لگتا، اس کو وہ بہت آسانی سے حل کر لیتے تھے۔ استاد نے کہا کہ تمھارا کیا ہوگا، یہاں تو دورہ پشتو میں ہوتا ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ عربی میں دورہ کرایا کریں۔ اب استاد کے لیے یہ کہنا مشکل ہوا کہ بھئی عربی میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب آدمی اس درجے کو پہنچ گیا کہ بخاری، مسلم، ترمذی پڑھے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں عربی نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد عربی میں دورہ شروع ہو گیا۔ مجھے بھی فائدہ ہو گیا۔ جب میری باری آئی تو دورۂ عربی میں ہی ہوتا تھا۔ کہیں کہیں وہ وضاحت کے لیے کچھ بات پشتو میں بھی بتا دیتے تھے۔ استاد کو عربی میں پڑھانے میں کوئی دقت نہیں تھی، طلبہ کچھ تھوڑے بہت چیں بجبیں ہوئے، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکا۔ بہت متبحر، بہت ہی اعلیٰ پایے کے استاذ تھے۔ ان کی اصول حدیث پر عربی میں ایک دو کتابیں بھی ہیں۔
اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ میرا نام والد نے صرف ’’محمدؒ ؒ ‘‘ رکھا تھا۔ عربوں میں تو اس کا بہت رواج ہے کہ مفرد نام ہوتا ہے، جیسے محمد، علی، احمد۔ ہمارے ہاں اکثر مرکب ناموں کا رواج ہے اور خاص طور پر اگر کسی کا نام اکیلا محمد ہو تو اسے بے ادبی سمجھتے ہیں۔ جب بھائی جان مجھے بنوری ٹاؤن میں داخل کروانے لے گئے تو جو صاحب رجسٹر پر نام لکھ رہے تھے، انھوں نے کہا کہ یہ اکیلا محمد کیا نام ہوا؟ مرکب نام ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب نے ایک سیکنڈ کے توقف کے بغیر کہا کہ محمد الغزالی لکھ دیں۔ پہلے یہ مسئلہ زیر غور نہیں آیا، نہ انھوں نے اس پرسوچا۔ بس چھٹتے ہی کہہ دیا۔ تب سے میرا یہ نام پڑ گیا۔ اسی طرح ہمارے والد کے ایک دوست تھے مولانا ابوالخیر مسلم علوی، اسلامی کاموں میں بہت پیش پیش رہتے تھے۔ انھوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تمہار انام محمود احمد ہے۔ کوئی لقب بھی ہونا چاہیے ، لقب کے بغیر نام اچھا نہیں لگتا۔ بھائی جان نے اسی وقت کہا کہ: محمود احمد غازی۔
اسی طرح ایک لطیفہ بھی عرض کر دوں۔ مرحوم ضیاء الحق کی شہادت ہوئی تو غلام اسحاق خان مرحوم نے بھائی صاحب کوبلا کر کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ انھوں نے پڑھا دی۔ اس کے چند ماہ بعد بے نظیر کی حکومت آگئی اور ایک دوسرارنگ پیدا ہو گیا تو ہمارے بچوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھیے، آپ کی بڑی شہرت ہوئی ہے کہ آپ نے ضیاء الحق کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ بے نظیر اس کی بہت مخالف ہے۔ اگراس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نماز جنازہ پڑھائی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے کہ میں کہوں گا کہ میں تمھاری بھی پڑھانے کو تیار ہوں۔ تو کتنا ہی گمبھیر مسئلہ ہو، الحمد للہ ان میں اس کو فوراً حل کر دینے کی خاص صلاحیت تھی۔
آپ حضرات نے علم میں ان کے توسع کا ذکر کیا۔ خالص درسی جو دائرہ ہے، اس سے باہر دینی علوم اور عصری علوم پر جو کچھ اس زمانے میں عربی اور اردو میں لکھا گیا، اس سے بہت پہلے سے انھوں نے ابتدائی زندگی سے ہی بہت استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دو اساتذہ انھیں بہت اچھے ملے۔ ان میں ایک تھے استاد محمد یوسف عطیہ۔ وہ ان چند اولین لوگوں میں سے تھے جو مصر سے تشریف لائے تھے۔ مولانا بنوری مرحوم کے مدرسے میں انھوں نے عربی زبان پڑھائی تو بھائی صاحب نے بہت استفادہ کیا۔ ان کے گھر بھی جاتے تھے۔ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو خط وکتابت بھی کرتے تھے۔ پھرایک بڑی عظیم شخصیت ہمارے ملک میں ہوئے ہیں مولانا عبد القدوس ہاشمی مرحوم۔ غالباً مولانا مجاہد الحسینی صاحب کو بھی ان سے تعارف حاصل ہوگا۔ ان سے بہت کسب فیض کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ صرف کتاب سے ہی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے بہت زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے اگر کسی چلتی پھرتی کتاب سے آپ صحبت کریں اور اکتساب فیض کریں۔ اس کی ان کوبڑی لگن تھی۔ جہاں کسی صاحب علم کو دیکھا، وہ بس اس کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ آپ نے سنا کہ صاوی شعلان صاحب آئے ہوئے تھے۔ ایوب خان مرحوم نے ان کو بلایا تھا اور ان کے ذمے اقبال کے کلام کا ترجمہ تھا۔ وہ ہمارے ادارۂ تحقیقات اسلامی کی لائبریری میں بیٹھے تھے۔ ان سے تعارف ہوا او ر ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہے۔ انھوں نے سوچا کہ یہی میرے کام کا آدمی نکلے گا۔ اس وقت بھائی جان اتنے کم عمر تھے کہ ڈاڑھی بھی پوری طرح نہیں نکلی تھی۔ انھوں نے ایک سال صاوی شعلان کے پایے کے ادیب اور شاعر کے ساتھ کام کیا جو بہت ہی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل آدمی تھے اور جناب ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے بجا کہا کہ کلام اقبال کے عربی ترجمے درجنوں ہیں، لیکن جو درجہ صاوی صاحب کے منظوم ترجمے کوحاصل ہوا ہے، کسی کو نہیں ملا۔ کہیں کہیں تو لگتا ہے کہ ترجمہ اصل سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔
ختم نبوت کے مسئلے سے انھیں کوئی خاص اعتنا نہیں تھا۔ جیسے ہر مسلمان اس سے واقف ہوتا ہے، وہ بھی واقف تھے، لیکن ایک موقع پر ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو سوال ہوا کہ کون وہاں پیش ہو کر اسلام کا موقف بیان کرے۔ سب علماء کرام نے جو اس سلسلے میں سرگرم تھے، ان کو کہا کہ آپ یہ کام کریں تو وہ اس پرتیار ہو گئے۔ ایک دفعہ وہ چیلنج قبول کر لیتے توپھر اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس میں ہمہ تن لگ جاتے تھے۔ پانچ ہفتے تک ان کا سپریم کورٹ میں بیان ہوا۔ یہ آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ دوسری طرف سے پوری دنیا کی قادیانی جماعت، اس کے نمائندے اور ان کے وکیل پوری تیاری کے ساتھ اعتراض کرنے کے لیے، جرح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرف سے مسلمان علما اور دوسرے لوگوں کی جماعت تھی جو ان کی مدد کرتی تھی، لیکن جتنی بھی مدد ہو، بہرحال سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا جہاں ہر بات کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ الحمد للہ پانچ ہفتے تک روزانہ صبح نو بجے سے ایک بجے تک ان کا بیان ہوا۔ وہ جب لکھا گیا تو تقریباً ساڑھے پانچ ہزار صفحوں پر محیط تھا۔ اب اس میں اس طرح کی بحثیں آئیں کہ ختم نبوت اسلام کا ایسا عقیدہ ہے کہ جو اس کامنکر ہو، وہ کافر ہے۔ انھوں نے چیلنج کیا کہ جناب، دلیل دیجیے۔ ختم نبوت کو define کیجیے، نبوت کو ڈیفائن کیجیے، وحی کو کیجیے، الہام کو کیجیے۔ مرزا صاحب کہتے تھے الہام آتا ہے، میں بروزی نبی ہوں، ظلی نبی ہوں تو نبوت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ بات جب آپ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے تو اس میں بہت سارے مقدمات ہیں۔ ہر مقدمے کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے تو بتائیے، اجماع کیا چیز ہے۔ اجماع پر بحث شروع ہو گئی۔ علیٰ ہذا القیاس مرزا صاحب صوفیہ کی بعض تحریروں کا سہارا لیا کرتے تھے تو تصوف پر بحث شروع ہو گئی کہ کشف کیا ہے؟ الہام کیا ہے؟ صوفیانہ انداز کا جو اکتساب علم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وحی کیا ہے جس کی بنا پر ایمان وکفر کا مسئلہ طے ہوتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔
اسی طرح ایک زمانہ آیا جب کچھ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو رہا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں اور شریعت کورٹ میں مسائل زیر بحث تھے۔ مرحوم ضیاء الحق صاحب اس میں کچھ پیش پیش تھے۔ بھائی صاحب کو اس میں کچھ حصہ لینے کا موقع ملا تو بعض مواقع پر ایسا لگتا تھا کہ شاید انھوں نے یہی کام ساری عمر کیا ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ ضیاء الحق صاحب نے جب جونیجو حکومت کو برخواست کیا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک شریعت آرڈیننس نافذ کریں جس کا مقصد فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیار سماعت میں توسیع کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ۸۱ء میں فیڈرل شریعت کورٹ بنی تھی تو اس کے اختیارات دو قسم کے تھے۔ ایک تو یہ کہ سیشن کورٹ میں جو حدود اور قصاص وغیرہ کے مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے خلاف اپیل شریعت کورٹ سنے گی اور اس کے بعد اپیل ہوگی سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بنچ میں۔ اس کا دوسرا اختیار جس کو original jurisdiction کہتے ہیں، یہ تھا کہ کوئی بھی شہری شریعت پٹیشن دائر کر سکتا ہے جس میں وہ پاکستان کے کسی بھی قانون کو یا قانون کے جز کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ قرآن وسنت سے متعارض ہے، لہٰذا اس کو کالعدم کیا جائے یابدلا جائے۔ شروع میں وفاقی شرعی عدالت کے اختیار سماعت سے مالی قوانین، دستور اور پروسیجر کو مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ بہت سے استثناء ات تھے جن میں کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ خاص وقت تک کے لیے تھے۔ ضیاء الحق صاحب چاہتے تھے کہ ایک شریعت آرڈیننس آئے جس میں یہ استثناء ات ختم کر دیے جائیں۔ ان کی لیگل ٹیم میں اس وقت جسٹس ارشاد حسن خان تھے جو بعد میں چیف جسٹس ہوئے۔ اس وقت وہ لاء سیکرٹری تھے۔ ان کے علاوہ عزیز منشی صاحب اٹارنی جنرل تھے اور شریف الدین پیرزادہ بھی تھے۔ ان تینوں حضرات نے ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر آپ آرڈیننس لائیں گے تو یہ دستور میں ترمیم ہے اور دستور میں ترمیم پارلیمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی جسے آپ نے ڈس مس کر دیا ہے۔ آرڈیننس تو قانون ہوتا ہے جو چھ مہینے کے لیے ہوتا ہے، تا آنکہ پارلیمنٹ اس کو منظور کرے یامسترد کرے۔ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی تو ہو سکتی ہے، دستور سازی نہیں ہو سکتی نہ دستور میں ترمیم ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ کام نہیں ہو سکتا۔
ضیاء الحق صاحب اس پر بہت frustrated ہوئے۔ ان دنوں ان پر اس خیال کا بہت غلبہ تھا کہ میں نے اب تک جو کیا ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ شاید بعض اہل ایمان وتقویٰ کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ اب وہ جانے والے ہیں تو ان کو بہت لگن تھی کہ کچھ ہو جائے۔ ہمارے بھائی صاحب کی موجودگی میں ان تینوں آدمیوں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ جی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جو چاہیں اس آرڈیننس میں لکھ دیں، لیکن وہ جو استثنا ہے کہ شریعت کورٹ مالیات سے متعلق معاملات کو نہیں سن سکتی، پروسیجر کو نہیں سن سکتی، کانسٹی ٹیوشن کے خلاف نہیں کچھ سن سکتی، اسی طرح ایک دو اور چیزیں ہیں، یہ استثنا ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ میٹنگ رات کے بارہ بجے تک چلتی رہی۔ ضیاء الحق صاحب بھی بہت دیر تک کام کرنے کے عادی تھے۔ میٹنگ کے بعد بھائی صاحب تھکے ہارے گھر آئے اور آ کر کہا کہ مجھے کچھ چائے یا کافی پلا دو، مجھے کام کرنا ہے اور کمرے میں بند ہو گئے۔ صبح کی نماز تک وہ دستور، دستورکی شرحیں اور اس سے متعلق کچھ اہم فیصلوں کا پلندہ جو وہ کہیں سے لے آئے تھے، پڑھتے رہے۔ ساری رات اس میں لگے رہے اور صبح کے قریب وہ اچھل پڑے اور انھوں نے مجھے بھی بتایا۔ انھیں بڑی خوشی ہوئی کہ کہیں ایک جگہ یہ لکھا ہوا مل گیا کہ کسی کورٹ کی جورس ڈکشن وہ ہوگی جو اس دستور میں طے کر دی گئی ہے اور جس کی وضاحت فلاں فلاں جگہ کی گئی ہے اور آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ یہ لکھا ہوا تھاکہ: by law۔ تو انھوں نے کہا کہ جب قانون کے ذریعے کسی عدالت کی جورس ڈکشن طے ہو سکتی ہے تو آرڈیننس جو ہوتا ہے، وہ قانون کا متبادل ہوتا ہے، اس لیے آرڈی ننس سے بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آرڈی ننس لایا جا سکتا ہے کہ شریعت کورٹ کے اختیارات پر قدغن کم کیے جائیں یا ختم کیے جائیں۔
اگلے دن وہ لیس ہو کر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ اب میٹنگ شروع ہوئی تو ضیاء الحق صاحب نے ان سے شاید کہا تھا کہ آپ تیاری کر کے آئیے گا۔ انھوں نے ضیاء الحق صاحب کے سامنے بہت مدلل انداز میں یہ ساری بات رکھ دی تو ضیاء الحق صاحب اپنی لیگل ٹیم پر بہت ناراض ہوئے۔ وہ عام طور ناراض نہیں ہوتے تھے،لیکن ہوتے تھے تو بہت زیادہ ہوتے تھے۔ وہ جو عربی میں کہتے ہیں کہ اتقوا غضب الحلیم تو غضب الحلیم تھا ان میں۔ انھوں نے ان حضرات یعنی شریف الدین پیرزادہ، جسٹس ارشاد حسن خان اور عزیز منشی سے کہا کہ میں نے تمھیں یہاں گھاس چرنے کے لیے بلایا تھا؟ تم اتنے دن سے مجھے دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو؟ جو کچھ کہہ سکتے تھے، انھوں نے کہا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب انھیں ڈانٹ پڑ رہی تھی تو مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگا کہ باہر نکل کر یہ میرا کیا حشر کریں گے۔ بہرحال وہ بات مانی گئی اور آرڈیننس بن گیا۔ ضیاء الحق صاحب نے نافذ بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد دن بے نظیر کی حکومت آئی، چھ مہینے گزر گئے اور پارلیمنٹ نے اس کو منظور نہیں کیا۔
یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ان کی لگن، commitment اور دلی شوق کی۔ دنیا کی تہذیب اور تمدن میں جوبھی کارنامے ہوئے ہیں، وہ شوق کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ تاریخ انسانی میں جو کچھ دنیاے انسانیت نے حاصل کیا ہے، وہ شوق اور عشق کا کرشمہ ہے۔ بڑے بڑے کارنامے اسی سے انجام پاتے ہیں۔ تو ان کو ایک شوق تھا، ایک عشق تھا اور میں نے ان کو پچاس سال دیکھا ہے۔ پچاس سال کے دوران وہ جس بات پرخوش ہوتے تھے، وہ یہی تھی کہ کوئی علمی کام ہو گیا، کوئی علمی نکتہ مل گیا، کوئی کتاب مل گئی، کوئی بات سمجھ میں آ گئی، کسی نے کوئی بات سمجھ لی، کوئی اچھا طالب علم ان کے پاس آکر اچھا کام کر گیا۔ کنفیوشس چینی فلسفی ہے۔ اس کا مشہو رجملہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھو، اس کی خوشی کے لمحات کودیکھو، اس کے غم کے لمحات کو دیکھو، اس کے حیرت کے لمحات کو دیکھو، اس کے دوست کو دیکھو، دشمن کو دیکھو، آدمی اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ علم دین کا حصول ، اس کا فروغ، اسی کے لیے وہ جیے، اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لی، حتیٰ کہ اپنی صحت کی طرف سے بے انتہا لاپروائی برتی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ انھوں نے زندگی میں کبھی کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا۔ کبھی بیمار نہیں ہوئے، ایک دن کے لیے صاحب فراش نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بیماریاں تو لگی رہتی ہیں انسان کے ساتھ، لیکن چھوٹی موٹی تکلیف کو کبھی خاطرمیں نہیں لاتے تھے۔ آخری دن چند گھنٹے وہ ہسپتال میں لیٹے۔ اس دوران وہ قرآن پڑھتے رہے اور زیادہ بات نہیں کی۔ پھر فجر کا وقت ہوا تو اسی بستر میں بیٹھے بیٹھے وضو کر لیا، ڈاکٹر سے پوچھا ہی نہیں۔ عموماً آئی سی یو، سی سی یو میں اتنی حرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارا بیٹا تھا۔ انھوں نے اس سے کہا جلدی میں کہ وضو کرواؤ، اس نے وہیں وضو کروا دیا۔ بستر میں نماز پڑھی اور پھر یہ جا وہ جا۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بھائی محمود
مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی
ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ، پاکستان کے مدیر مکرم، مولانا عمار خان ناصر صاحب کا ارشاد ہے کہ راقم سطور، مجلہ الشریعہ کے پروفیسر محمود احمد غازی نمبر کے لیے کچھ لکھ کر پیش کرے۔ میں اس محترم فرمائش کی تکمیل کرنا چاہتاہوں مگر حیران ہوں کہ کیا لکھوں:
چگونہ حرف زنم دل کجا، دماغ کجا
مگر بہر صورت کچھ نہ کچھ حاضر کرنا ہے، اس لیے چل مرے خامے بسم اللہ!
محمود غازی صاحب برصغیر ہند کے نامور وممتاز فاضل، عالم، دانشور، مصنف ومترجم، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر [شیخ الجامعہ]، پاکستان کی عدالت عالیہ کی شریعت بنچ کے سینئر جج، مذہبی امور اورحج کے لیے حکومت پاکستان کے وفاقی مرکزی وزیر، پاکستان کے متعدد سربراہان حکومت کے مشیر ومعتمد، پچاسوں قومی اوربین الاقوامی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں ممتاز مبصر ومقالہ نگار، پینتس چھتیس کتابوں کے مصنف اور مختلف کتابوں کے عربی، اردو، انگریزی مترجم، یعنی اکثر علمی کمالات سے پوری طرح بہرہ ور اور دنیاوی مناصب واعزازات میں بلند سے بلند مرتبہ پر فائز! مگر ہم اہل خاندان خصوصاً کاندھلہ میں مقیم رشتہ داروں کو نہ ان میں سے اکثر عہدوں اور مناصب کا علم اورنہ ان کا ان سے وابستہ معاملات، منافع ومباحث سے کچھ واسطہ۔ ہم سب کے لیے محمودغازی صاحب نہ جسٹس صاحب تھے، نہ شیخ الجامعہ ،نہ وزیرباتدبیر اورصدرپاکستان کے مشیرومعتمد۔ ہم سب خصوصاً راقم سطور اورقریبی عزیزوں کی زبانوں پر وہ صرف بھائی محمود تھے۔ ہمیشہ اسی نام سے پکارے گئے اور بھائی محمود بھی ہم سب اہل خاندان سے صرف اور صرف اسی رشتے سے ملے۔ نہ ان پر کسی مقام ومرتبہ اورعہدہ ومنصب کا احساس واثر نظر آیا، نہ اس کا تذکرہ ہوا۔ جب ملتے خوب ملتے، بے تکلفی سے، بلاکسی خیال کے۔ سب طرح کی اچھی بری باتیں ہوتیں، عزیزوں رشتہ داروں کے احوال وکوائف کی بات ہوتی، واقعات جہاں کادفتر کھلتا، تازہ علمی مباحث اور کتابوں کی خبر ملتی اور ہراک عنوان پر کچھ نہ کچھ تبادلہ خیال ہوتا۔ اس کی وجہ بھائی محمود کے مزاج کی سادگی، کاندھلہ کے مشہورعلمی دینی صدیقی خاندان سے ان کی ننھیالی نسبت اور زندگی کے ابتدائی چندسال کاندھلہ میں گزارنے کا اثر تھا جس کابھائی محمودنے ہمیشہ بے حدخیال رکھا اوراس رشتہ وتعلق کوپورے اہتمام سے، پورے احترام سے اور تواتر کے ساتھ ہمیشہ نبھایا۔
کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھائی محمود کا اگرچہ اصلی وطن اور خاندانی سلسلہ تھانہ بھون کے ممتاز فاروقی خاندان سے ہے، مگر ان کے بچپن کا اکثر حصہ کاندھلہ میں گزرا۔ بھائی محمود کی والدۂ محترمہ مدظلہا کاندھلہ کے معروف صدیقی خاندان کی مؤقر خاتون ہیں۔ بھائی محمود کے نانا حکیم قمرالحسن صاحب، راقم سطور کے والد ماجد مدظلہ العالی کے بڑے بھائی [میرے تایا] تھے۔ اس پہلو کی بعض تفصیلات کے بغیر یہ گفتگو مجمل وناتمام رہے گی، اس لیے اس کے بعض گوشوں کاتذکرہ ضروری ہے۔
کاندھلہ کے اس خاندان کے ایک بابرکت فرد، مولوی رؤف الحسن صاحب کاندھلوی تھے جو [شیخ الحدیث حضرت مولانا محمدزکریا کاندھلوی کے والد ماجد] حضرت مولانا محمدیحییٰ اور مروج تبلیغ، حضرت مولانا محمدالیاس صاحب کاندھلوی کے حقیقی ماموں بھی تھے۔ ان کا سلسلۂ نسب یہ ہے:
مولوی رؤف الحسن [وفات:۱۳۶۴ھ۔۱۹۴۵ء] بن مولاناضیاء الحسن صادق[م۱۳۱۵ھ۔ ۱۸۹۸ء] بن مولانا نورالحسن [۱۲۸۵ھ۔۱۸۶۸ء] بن مولانا ابوالحسن [م۱۲۶۱ھ۔۱۸۵۳ء] بن حضرت مفتی الٰہی بخش کاندھلوی [م۱۲۴۵ھ۔۱۸۲۹ء] رحمہم اللہ‘‘
مولوی رؤف الحسن صاحب کے پانچ فرزند ہوئے:
(۱) مولانا حکیم نجم الحسن صاحب [م:۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء]
(۲) مولانا احتشام الحسن صاحب، معروف مصنف اور حضرت مولانا محمدالیاس صاحب کے رفیق [م: ۱۳۹۲ھ۔۱۹۷۱ء]
(۳) مولوی حکیم قمر الحسن صاحب فاضل، جامعہ طبیہ دہلی[م:۸/شوال۱۳۶۲ھ۔۸ستمبر۱۹۴۳ء]
(۴) مولانا اظہارالحسن صاحب ،جو مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں اوراس کے بعد مرکزتبلیغ نظام الدین، دہلی کے عملاً سربراہ اور تبلیغ کے موجودہ ذمہ دار مولوی محمد سعد صاحب کے ناناتھے۔ [م:۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء]
(۵) حضرت مولانا افتخارالحسن صاحب مدظلہ [جو راقم سطور کے والد ماجدہیں] ولادت:۱۱جمادیٰ الاولیٰ ۱۳۴۰ھ/۱۰جنوری۱۹۲۲ء
اورتین دختر:
الف: جویریہ خاتون، زوجہ حضرت مولانا محمدالیاس صاحب کاندھلوی ۔
ب: امت الدیان، زوجہ مولوی ظہیرالحسن صاحب کاندھلوی۔
ج: امت المتین، زوجہ اولیٰ شیخ الحدیث مولانا محمدزکریا کاندھلوی۔
فرزندوں میں سے تیسرے، حکیم قمرالحسن صاحب کے کوئی پسری اولاد نہیں تھی، دوبیٹیاں تھیں۔ بڑی کی شادی تھانہ بھون کے فاروقی خاندان میں مولانا محمداحمدصاحب تھانوی سے ہوئی۔ یہی بھائی محمود کی والدہ محترمہ ہیں۔ دوسری بہن کا نکاح کاندھلہ کے ایک فاضل، مولوی حکیم خلیق الرحمن صاحب سے ہوا۔ وہ بھی ۱۹۴۷ء کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ سنجھورہ، سندھ میں رہے۔ آخر میں سکھر آگئے تھے، ان کے اہل خانہ وہیں ہیں۔
مولانا محمداحمد کے دوبیٹے ہوئے: محموداحمد[ولادت:۱۹۵۰ء] اور محمد [ولادت:۱۹۵۳ء]۔ بھائی محمودنے زمانہ طالب علمی سے اپنے نام کے ساتھ غازی کا اضافہ کر لیا تھا اور چھوٹے بھائی کے نام کے ساتھ الغزالی کا لاحقہ استعمال ہوتاہے، پروفیسر ڈاکٹر محمدالغزالی [مدیر مجلہ الدراسات الاسلامیۃ اسلام آباد] حفظہ اللّٰہ۔
بھائی محمود کے والد محترم، دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن میں ملازم تھے، اس لیے ان کی والدہ اکثراپنے میکہ کاندھلہ رہتی تھیں۔ یہیں بھائی محمود کی نشوونما ہوئی اوریہیں قرآن کریم کی تعلیم کی ابتدا بھی ہوئی۔ بھائی محمودکی نانی صاحبہ کے مکان سے چند قدم کے فاصلہ پر،کاندھلہ کی جامع مسجد ہے۔ اس مسجدمیں ایک پرانامدرسہ تھا جس کو ۱۳۰۰ھ میں حضرت مولانا رشیداحمدگنگوہی کی سرپرستی میں حضرت مولانا کے ایک شاگرد،مولانا حکیم صدیق احمدصاحب کاندھلوی نے قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ اس وقت تک خوب کامیاب اور متحرک ورواں دواں تھا۔ اس میں حفظ کے درجات بھی تھے،ناظرہ کے بھی اور متوسطات تک عربی فارسی کی بھی عمدہ تعلیم ہوتی تھی۔ اسی مدرسہ کے ایک معلم قرآن، حافظ عبدالعزیز صاحب تھے جو کاندھلہ سے ملحق گاؤں کھندراؤلی کے باشندے تھے مگر کاندھلہ آگئے تھے۔ درجہ حفظ وناظرہ کے استاد تھے۔ بھائی محمود نے تعلیم کی ابتدا ان سے کی اوربہت کم عمری میں ایک پارہ ختم کر لیا تھا۔
سنہ۱۹۵۴ء میں بھائی محمود کے والد محترم نے اور بہت سے عزیزواقربا کے ساتھ پاکستان جانے کا ارادہ کرلیا اوراپنے وطن کوخیر باد کہتے ہوئے نئے وطن، نئی سرزمین کے لیے روانہ ہوگئے۔ پاکستان پہنچ کر کراچی میں قیام ہوا۔ کیونکہ دہلی میں مولوی محمداحمدصاحب پاکستان ہائی کمیشن میں ملازم تھے، اس لیے کراچی میں سرکاری دفتر میں تقرر ہوگیا۔ کراچی میں قیام اور ملازمت کا انتظام ہوتے ہی بھائی محمودکی تعلیم کی طرف توجہ کی۔ گھر کے قریب ایک مدرسہ تھا جس میں قاری وقاء اللہ صاحب پانی پتی سے [جو ہندوستان کی ایک معروف شخصیت مولانا لقاء اللہ پانی پتی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے] کاندھلہ کے سلسلۂ تعلیم کی تجدید ہوئی۔ ان سے اور اسی مکتب کے ایک اوراستاد، حافظ نذیر احمدصاحب سے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ حفظ نوعمری میں صرف نوسال کی عمر میں مکمل ہوگیاتھا۔
حفظ کے بعد دورکیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت مولانا محمدیوسف بنوری کے مدرسہ میں عربی تعلیم کے لیے داخل کر دیے گئے۔ مدرسۂ مولانا بنوری میں چارسال تک پڑھا جس میں خودمولانا بنوری سے بھی تلمذ کی سعادت میسر آئی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ بھائی محمودکے وہ استاذ جو اصول الشاشی پڑھارہے تھے، کسی ملازمت پر تقرر کی وجہ سے درمیان سال میں سعودی عرب چلے گئے تھے۔ اس وقت ان کے سبق مولانابنوری نے پڑھائے تھے۔ اسی مدرسہ میں مولانا عبدالرشید نعمانی سے بھی تلمذ ہوا اور مولانا عبدالقدوس ہاشمی سے بھی رابطہ رہا۔ مولانا ہاشمی سے اگرچہ باضابطہ تلمذوتعلیم تو نہیں ہوئی، لیکن کثیر استفادہ کاموقع ملا جو بعد میں بھی جاری رہا۔ بھائی محمودکوکچھ وقت مدرسہ ٹنڈو اللہ یار میں بھی گزارنے کا موقع ملا۔ یہاں حضرت مولانا ظفراحمدعثمانی اور حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ پاکستان کامرکزی دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ سرکاری ملازمین بھی آہستہ آہستہ کراچی سے اسلام آباد پہنچتے رہے۔ انہی میں محمودصاحب کے والد محترم مولانا محمداحمد صاحب تھانوی بھی تھے۔ اس وقت سے اس گھرانہ کا قیام اسلام آباد میں ہوا جو آج تک اسی طرح ہے۔
بھائی محمود کی تعلیم کا سلسلہ ناتمام تھا، اس لیے ان کا راول پنڈی میں شیخ القرآن ، مولانا غلام اللہ خاں صاحب کے مدرسہ میں داخلہ کرایاگیا۔ اس مدرسہ میں درس نظامی کی آخری کتابیں مکمل کیں اور دورۂ ۂحدیث پڑھا۔ مولانا غلام اللہ صاحب کے مدرسہ کے ایک بڑے استاذ حدیث، مولانا عبدالشکور کامل پوری [وفات:رجب ۱۳۹۰ھ/ستمبر۱۹۷۰] (۱) سے سنن ابی داود اور موطاامام مالک پڑھیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب ،حضرت مولانا خلیل احمد انبیٹھوی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا محمدیحییٰ کاندھلوی اورحضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری رحمہم اللہ کے شاگردتھے۔ بہت عمدہ درس دیتے تھے۔ اگرچہ حنفی تھے، مگر درس محدثانہ شان کا محققانہ ہوتاتھا جس کی وجہ سے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوجاتی تھی کہ مولانا غیر مقلد یا اہل حدیث ہیں۔ مولانا حنفی تھے، لیکن محدثانہ تحقیقات صاف بیان فرماتے تھے جس سے مولانا کے اہل حدیث ہونے کا شبہ گزرتاتھا۔ چونکہ اس مدرسہ کے اکثر طالب علم پٹھان یا صوبہ سرحد [موجودہ نام، پختونخواہ] وغیرہ کے تھے، اس لیے مولانا کامل پوری، پشتو میں درس دیتے تھے۔ چند دنوں کے بعد بھائی محمود نے گزارش کی کہ میں پشتو نہیں جانتا، اگر درس عربی میں ہو تو میرے لیے استفادہ کا زیادہ موقع ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے عزیز شاگرد کی رعایت فرماتے ہوئے عربی میں درس دینا شروع کر دیا۔ اس سے اگرچہ کئی طلبہ ناراض ہوئے اورکچھ بات چلی، مگر پھر سب مطمئن ہوگئے تھے، درس عربی میں ہوتارہا۔ مولاناعبدالشکور کامل پوری ،۱۹۴۷ء سے پہلے مدرسہ مظاہرعلوم میں مدرس تھے، حضرت مولانا خلیل احمدانبیٹھوی کے بھی شاگر دتھے اوران سے بھائی محمود کے والد صاحب اور نانا دونوں نے پڑھاتھا۔ بھائی محمودکو بھی ان سے پڑھنے کی سعادت ملی۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھائی محمودنوعمری میں، اس وقت کے ایک بڑے مربی اور عارف حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری سے بیعت ہوگئے تھے۔ مولانا کے والد، شیخ الحدیث مولانا محمدزکریا کی قیام گاہ (کچے گھر) سہارنپور میں، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب سے بیعت ہورہے تھے۔ حضرت شیخ نے بھائی محمود کومخاطب کر کے فرمایا: تو بھی بیعت ہوجا! تو بھائی محمود بھی حضرت رائے پوری سے باقاعدہ بیعت ہوگئے تھے۔ میں نے سناہے کہ بھائی محمود کو، جو :’’بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی‘‘ کی حیثیت بھی رکھتے تھے، پاکستان اور بیرون پاکستان کے ایک سے زائدمشائخ طریقت سے اجازت وخلافت بھی حاصل تھی، مگر اس کی تفصیل معلوم نہیں۔
جب اس کارخانۂ ہستی میں ہماری آنکھیں کھلیں اور کچھ شعور پیدا ہوا، وہ عجیب اپنائیت ومحبت کادور تھا۔ میل ملاقات، ایک دوسرے سے رابطہ تعلق رکھنے، رشتے، عزیزداری نباہنے کادورتھا۔ گھر اگرچہ ماشاء اللہ سب کے علیحدہ علیحدہ اور خوب بڑے بڑے تھے، ہرطرح کی ہر چیز کی فراوانی تھی اورافراد بھی ماشاء اللہ کم نہیں تھے، مگر اپنی الگ حیثیت، علیحدہ گھروں اور ذرائع معاش کے باوصف، سب عزیزایک دوسرے سے گویا جسم وجان سے پیوست تھے۔ ہرایک دوسرے پر جان چھڑکتاتھا، ہروقت ایک دوسرے کے یہاں آناجانا، ملاقات اور خیروخبرجاری رہتی تھی جس کی وجہ سے سب ایک دوسرے کے لیے افراد خانہ کی حیثیت رکھتے تھے اورخاندان کے سب لوگ مل کر، ایک گھرانہ کی طرح رہتے تھے۔ اس وقت کی محبتوں اورمخلصانہ روابطوں اور تعلقات کاآج کل کے ناپرسان احوال دور میں، اندازہ بھی نہیں کیاجاسکتا۔ گویا:
خواب تھاجو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا
انہی روابط وقرابت کی وجہ سے بھائی محمود کی والدہ صاحبہ ۱۹۶۵ء تک [جب ہندوپاکستان کے تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے اور آنے جانے کی ایسی پریشانی نہیں تھی] تقریباً ہرسال اپنی والدہ صاحبہ سے ملاقات کے لیے ہندوستان آتی تھیں، ہندوستان میں عموماً دوتین مہینہ قیام رہتا تھا۔ اس وقت بھائی محمود اپنی خاندانی مادرعلمی، مدرسہ جامع مسجدکاندھلہ کے طالب علم بن جاتے تھے۔ قرآن شریف کی تعلیم ودور کی بات ہو یا فارسی عربی درسیات کی، دونوں کے سبق کاندھلہ کے مدرسہ میں جاری رہتے تھے۔ اچھے پڑھانے والے بھی موجود تھے، اس لیے پڑھنے کابھی ایک مزا تھا۔ اس دور میں اول استاد، حافظ عبدالعزیز صاحب مرحوم کے علاوہ، مدرسہ کے عربی کے استادوں، مولانا عبدالجلیل صاحب بستوی اور مولانا زین الدین صاحب بستوی سے بھی تعلیم کا کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری رہتاتھا اور پاکستان میں زیردرس کتابوں کے اسباق کی تکمیل ہوتی رہتی تھی۔ بھائی محمود، مولانا عبدالجلیل صاحب کی علمی صلاحیت اورطریقۂ تعلیم ودرس کے مداح تھے۔
اس وقت سے بھائی محمود سے جو واقفیت اور رابطہ بنا تھا، وہ بحمداللہ، ملک بلکہ ملکوں کے فاصلوں، مناصب ومصروفیات، عہدۂ وترقیات کے باوجود ہمیشہ اسی طرح رہا۔ مجھے اس اعتراف میں ذرا بھی تکلف وتأمل نہیں کہ اگرچہ رشتہ میرا بڑا تھا، مگر بھائی محمود عمر کے علاوہ، علم وکمال اورتحریروقلم سے رہنمائی اور علم آفرینی کے اس درجہ پر تھے کہ ہمارے جیسوں کاوہاں گزر بھی نہیں، مگراس کے باوجود ہرطرح کی گفتگوہوتی۔ علمی مباحث بھی چھڑتے، ارباب سیاست کابھی ذکر آتا، ان پر کھٹے میٹھے تبصرے بھی ہوتے، خصوصاً پاکستان کے اہل سیاست واقتدار پر ان کی رائے سننے کی ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ کئی شخصیات ومعاملات میں ان کی رائے متعارف رائے اورنظریہ سے خاصی مختلف مگر سوچی سمجھی اورجچی تلی ہوتی تھی۔ وہ اس اعتماد سے بات کرتے تھے اوراس کے ایسے گوشے سامنے لاتے تھے کہ دوسرا پہلو ثابت کرنا مشکل ہوجاتاتھا اور ہم ایسے افراد جو ان معاملات سے براہ راست وابستہ نہیں، بھائی محمودصاحب کو صاحب البیت یاد انائے راز سمجھ کر خاموش رہ جاتے تھے۔
بھائی محمودصاحب جب کبھی ہندوستان آتے، کسی سیمینار میں، پروگرام میں، سرکاری مصروفیت سے، کاندھلہ کے لیے ضروروقت نکالتے تھے۔ بعض مرتبہ توموقع نہ ہونے کی وجہ سے آناجانا ہی ہوتا تھا، بمشکل گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قیام اور ملاقات رہتی، مگر آتے تھے اوراس کا اہتمام کرتے تھے۔ مجھے بھائی محمودکے کمالات وصفات میں یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ اپنی بڑائی کے باوجود ہمیشہ خورد بن کر ملتے تھے۔ پوری زندگی انہوں نے اپنی کسی بات سے، طرزعمل سے بلکہ اشارہ سے بھی اس کااحساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کس حیثیت ومقام کے شخص ہیں اور ان کی کیسی منزلت ہے۔ یہی انداز خط وکتابت میں بھی تھا۔ میرا ہمیشہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی فون پر رابطہ اور خط وکتابت رہتی تھی۔ پاکستان باربار فون کرنا اورلمبی بات چیت تو خلاف احتیاط تھی، مگر جب وہ پاکستان سے باہر ہوتے تو کئی مرتبہ فون پر رابطہ ہو جاتا تھا، خصوصاً آخر میں جب قطر میں تھے، کئی مرتبہ گفتگو رہی اور کبھی کبھی تبادلہ خطوط بھی ہوتاتھا جس میں سے غالباً اٹھارہ بیس خط محفوظ بھی ہیں۔ ان میں سے آخری دوخط یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔
میں نے مولانا ئے روم [شیخ جلال الدین رومیؒ ] کے سات سو سالہ جشن کے موقع پر مولانا روم پر ایک خاص شمارہ نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کا اپنے مجلہ احوال وآثار میں اعلان بھی کر دیا تھا اور اس میں تعاون ومضامین کے لیے ہند وپاکستان کے بیسوں اہل علم کی خدمات میں عریضہ اور سوال نامہ بھی بھیج دیاتھا، مگر چھے سات کے علاوہ کسی نے خط کی بھی رسید نہیں دی، مضامین ورہنمائی کا تو کیا ذکر ہے، اس لیے وہ ارادہ عمل میں نہ آسکا۔ جن لوگوں نے حوصلہ افزا جوابات دیے اور بھرپور تعاون کا وعدہ کیا، ان میں سب سے پہلا نام بھائی محمود کا ہی ہے۔ بھائی محمود نے میرے خط کے جواب میں دوخط لکھے تھے۔ ان سے غازی صاحب کی وسعت نظر، قوت اخذواستنباط اور سیلانئ ذہن کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خطوط ملاحظہ ہوں:
مکتوب اول:
خال مکرم ومحترم جناب مولانا نورالحسن راشد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
گرامی نامہ مؤرخہ ۶؍صفر المظفر۱۴۳۰ھ چند روز قبل اسلام آباد پر ملا۔ شاید آں محترم کے علم میں ہو کہ میں آج کل قطر میں مقیم ہوں۔ موسم گرما کی تعطیلات کے سلسلہ میں اگست کے وسط تک یہاں اسلام آباد میں رہوں گا۔
اس اطلاع سے ازحد خوشی ہوئی کہ مفتی الٰہی بخش اکیڈمی مولانا روم کی آٹھ سو سالہ پیدائش کی یادگار تقریبات کے موقع پر مثنوی پر ایک خصوصی شمارہ شائع کرنے کا پروگرام بنارہی ہے۔ ایں کار از تو آید ومرداں چنیں کنند! میری طرف سے دلی مبارک قبول فرمائیے۔
میری ناچیز رائے میں مجوزہ مقالات وعنوانات کی فہرست میں، مندرجات مثنوی اور پیغام مثنوی پر مزید اضافہ کی ضرورت ہے۔ یہ اضافے درج ذیل خطوط پر ہو سکتے ہیں:
(۱) مولانا روم اور تجدید فکراسلامی
(۲) مثنوی کا علم کلام
(۳) اشعری اور ماتریدی کلام، مثنوی کی روشنی میں
(۴) وحی ورسالت مثنوی کی روشنی میں
(۵) پیررومی اورمرید ہندی، ایک تقابلی مطالعہ
(۶) احادیث مثنوی پر ایک نظر (اصول حدیث کی روشنی میں)
(۷) مثنوی اور مکتوبات امام ربانی: تجدید واصلاح تصوف کے دواہم مآخذ
(۸) مثنوی اور حدیقۃ الحقیقہ: ایک تقابلی مطالعہ
(۹) مولانا شیخ محمد اور مفتی الٰہی بخش کے تکملہ جات مثنوی
(۱۰) کلید مثنوی پر حاجی صاحب کی شرح مثنوی کے اثرات
(۱۱) مثنوی اورحکمت شریعت
(۱۲) مثنوی اور مسئلہ وحدۃ الوجود
(۱۳) مثنوی اور تصور ارتقاء
(۱۴) مثنوی کاتصور تعلیم وتربیت
(۱۵) حکایات مثنوی کے مآخذ
(۱۶) مثنوی میں تفسیر قرآن کا اسلوب
سردست یہ چند ممکنہ عنوانات ذہن میں آرہے ہیں۔ مثنوی سامنے ہو تو اور بہت سے عنوانات تجویز کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تومیں عنوان ۱، ۲یا ۱۱ میں کسی ایک پر خامہ فرسائی کر سکتا ہوں۔
حضرت جدمکرم ومحترم مدظلہ العالی کی خدمت میں سلام نیاز اور دیگر اعزہ کو سلام ودعا۔
والسلام
نیازمندمحموداحمدغازی
۷؍جولائی۲۰۰۹ء
مکتوب دوم:
خال مخدوم ومعظم جناب مولانا نورالحسن راشد صاحب کاندھلوی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امیدہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے!
کل پرسوں ایک عریضہ ارسال خدمت کیاتھا، ملاحظہ سے گذرا ہوگا۔ رات مثنوی پر ایک سرسری نظر ڈالی تو بعض نئے موضوعات ذہن میں آئے جو خدمت عالی میں پیش ہیں:
(۱) مولانا کا فلسفۂ اخلاق
(۲) مکارم اخلاق : مثنوی کی روشنی میں
(۳) رذائل اخلاق: مثنوی کی روشنی میں
(۴) مولانا کی تنقید مسیحیت
(۵) مولانا کی تنقیدیہودیت
(۶) مثنوی کاتصور جہاد
(۷)معجزہ اور معجزات بندی مثنوی کی روشنی میں
(۸) نبوت وانبیاء [واِن شئت قلت] منصب نبوت اوراس کے حاملین، مثنوی کی روشنی میں
(۹)مقام نبوت اور مقام ولایت مولانا کی نظرمیں
(۱۰) مولانا کا اسلوب نعت گوئی
(۱۱)مولانا کا اسلوب تفسیر
(۱۲) مثنوی اور فلسفۂ یونان پر نقد
(۱۳) کشاکش عقل ودل، مثنوی کی روشنی میں
(۱۴) مولانا کاتصور مدت وحیات
(۱۵) مسئلہ جبر وقدر اور مثنوی
(۱۶) نفس انسانی اور اس کے مدارج
(۱۷) مثنوی کے مذہبی استعارے اور ان کی معنویت
(۱۸) آتش وخلیل کا استعارہ، رومی اور اقبال کے کلام میں
(۱۹) مثنوی کی باطنی تفسیریں: ایک تنقیدی مطالعہ
(۲۰)’’ ہست قرآں درزبان پہلوی‘‘
والسلام
نیازمند: محمودغازی
۹؍جولائی۲۰۰۹ء
کوئی موقع ہوگا توان شاء اللہ بعض چیزیں اور پیش کی جائیں گی۔
ہمارے بابا
ماریہ غازی
دنیا کے لیے بلاشبہ وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی تھے، مگر ہمارے لیے وہ صرف ’بابا‘ تھے۔انھوں نے کبھی گھر میں یہ ظاہر نہیں کہا کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ ان کے علم وتقویٰ کے بارے میں تو خاندان والوں کو بخوبی علم تھا، مگر دنیا ان سے کتنی محبت رکھتی ہے، اس کا اندازہ ان کے انتقال کے بعد ہوا۔ جس طرح لوگ دیوانہ وار ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور جوق در جوق تعزیت کے لیے آئے، اس سے صحیح معنوں میں ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوا اور بے پناہ رشک آیا۔ لوگوں کی محبت اور عقیدت کو دیکھتے ہوئے وہ حدیث یاد آتی ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت رکھتا ہے، دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔
باوجود اتنی مقبولیت کے، گھر میں وہ بالکل عام آدمی کی طرح رہا کرتے تھے۔ بہت ہی مہربان رویہ، نرم خو لہجہ۔ کبھی کسی کو ڈانٹنا تو کجا، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ گھرمیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ رات کو سب گھر والوں، خصوصاً دادی صاحبہ کے پاس بیٹھا کرتے اور ہلکی پھلکی پرمزاح گفتگو کیا کرتے تھے۔ بیرون ملک سفر کے دوران میں پیش آنے والے دلچسپ واقعات سنایا کرتے تھے۔باتوں باتوں میں نصیحت بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن انداز اتنا اچھا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو ناگوار نہیں گزرا۔ سنت کے مطابق اکثر پہیلی کی شکل میں سوال پوچھتے اور اکثر وبیشتر اس پر انعام بھی رکھا کرتے تھے کہ جو اس سوال کا جواب دے گا، اس کو سو روپے انعام دوں گا۔ کبھی کبھی انعامی رقم ایک ہزار روپے بھی ہوتی تھی۔ انعام کی رقم سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ سوال کس نوعیت کا ہے۔ اگر ہزار روپے ہوتے تو بغیر سوچے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم! اس طرح ہلکے پھلکے انداز میں بڑے بڑے مسائل سمجھا دیا کرتے تھے اور کسی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی باقاعدہ تعلیم ہو رہی ہے۔ اقبال کی شاعری سے خاص شغف تھا۔ کبھی کسی شعر کا ایک مصرعہ بتا کر اگلا مصرعہ پوچھتے، کبھی کسی شعر کا مطلب دریافت کرتے اور کبھی یہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ، یہ شعر کس شاعر کا ہے۔
اپنے مقام ومرتبہ کا اظہار گھر والوں کے سامنے تو کیا، رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں کرتے تھے۔ گھر میں مہمان داری بہت زیادہ تھی اور ہر کسی کی خوب خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ بچوں بڑوں، سب کو مناسب وقت دیتے تھے۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے کئی طرح کے کھانے پکواتے اور سیر وتفریح کا بھی انتظام کیا کرتے تھے۔ گھر میں جو بھی بچے آتے، ان کو اپنے بچوں ہی کی طرح سمجھتے تھے۔ جب ہمیں جیب خرچ دیتے تو جو بچے مہمان آئے ہوتے، ان کو بھی اتنی ہی خوشی اور پیار سے پیسے دیتے تھے۔ دوسروں کو تحفے تحائف دینے اور کھانے پلانے سے بے حد خوش ہوتے تھے۔ مہمانوں کے لیے ہمیشہ بہت اہتمام سے تحائف منگایا کرتے تھے اور خود بھی جب بیرون ملک جاتے تو سب کے لیے الگ الگ تحائف لے کر آتے تھے۔ عید کے موقع پر ہمیشہ ہمیں چاند رات کو چوڑیاں خریدنے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اتنی عزت اور مقام ومرتبہ کے باوجود دل میں تواضع اور انکسار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کسی کے گھر جاتے تو خواہ کتنی ہی بے آرامی محسوس ہوتی، کبھی اظہار نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرتے کہ بہت آرام اور راحت سے ہیں۔
دل میں تقویٰ بہت زیادہ تھا۔ سرکاری چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔جو اپنا جائز حق ہوتا، اکثر وہ بھی چھوڑدیا کرتے تھے۔ اگر کوئی نشان دہی کرتا بھی تو فرماتے کہ اگر سب کچھ یہیں لے لیں گے تو پھر وہاں کیا لیں گے! بہت شروع سے سرکاری گاڑی ملی ہوئی تھی، مگر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کو چلائے۔ یا تو سرکاری ڈرائیور چلاتا تھا یا خود چلاتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ قانون کے خلاف ہے کہ میرے یا ڈرائیور کے علاوہ کوئی اور اس کو چلائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں گاڑی ہونے کے باوجود چچا (ڈاکٹر محمد الغزالی) ٹیکسی یا بس سے دفتر گئے۔ گھر کے کام کے لیے جب بھی گاڑی استعمال ہوتی تو اس کا الگ سے حساب کر کے پیسے جمع کرایا کرتے تھے۔ کبھی کسی معاملے میں سختی نہیں کی، لیکن اس معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کیا اور بہت سختی سے سب سے اس پر عمل کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ دفتر کی طرف سے جو اخبار بھی گھر میں آتے، وہ بھی اکٹھے کر کے واپس جمع کروایا کرتے تھے۔
بچپن سے کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ طالب علمی کے زمانے کی کتابیں بھی ابھی تک حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں۔ اندرون ملک، بیرون ملک جہاں کہیں بھی جاتے، کتابیں ضرور خرید کر لاتے اور بہت احتیاط سے رکھتے تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو کتاب کا ادب نہیں کرتا، اسے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔کتاب پر لکھنے کے سخت خلاف تھے۔ اپنی کتابوں کو ہمیشہ مضمون کے لحاظ سے ترتیب وار رکھا کرتے تھے۔ تفسیر، حدیث، علوم الحدیث، فقہ، اصول الفقہ، سیرۃ، رجال، عقیدہ، علم الکلام، مقارنۃ الادیان، قانون، فلسفہ، معاشیات ، اردو، انگریزی، فارسی ادب حتیٰ کہ طب یونانی کے بارے میں بھی کتابیں ان کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ انھوں نے زندگی میں ہزاروں کتابیں جمع کیں اور ہر کتاب کے بارے میں انھیں زبانی یاد ہوتا تھا کہ کون سی الماری میں کس جگہ رکھی ہوئی ہے۔
ہمارے لیے بھی شروع سے ہی سبق آموز کہانیوں کی کتابیں لایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ہمیں نسیم حجازی کے ناول بھی لا کر دیے۔ علم اور تعلیم سے ان کو بے پناہ دلچسپی تھی۔ روزانہ جب میں یونیورسٹی سے واپس آتی تو پوچھتے تھے کہ آج کس کس مضمون کی کلاس ہوئی اور کیا پڑھا؟ اسکول کی ابتدائی جماعتوں سے ان کا یہی معمول تھا۔ یونیورسٹی میں جب مجھے کوئی اسائنمنٹ ملتی تو میں اس پر ان کے ساتھ اچھی طرح ڈسکس کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس موضوع سے متعلق کتابوں کی نشان دہی کرتے تھے اور جب اسائنمنٹ تیار ہو جاتی تو بہت دلچسپی سے اس کو پڑھا کرتے تھے اور غلطیوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اکثر وبیشتر انعام بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم بہنوں کا جب بھی امتحانات میں اچھا رزلٹ آتا تو نہایت خوشی کا اظہار کرتے، دعوت کا اہتمام کرتے اور تحائف دیا کرتے تھے۔
کھیلوں میں بھی انھیں وہی کھیل پسند تھے جن میں کوئی تعلیمی پہلو ہو۔ بہت بچپن سے ہمارے ساتھ تعلیمی تاش کھیلتے کہ اس سے اردو اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر جب سب لوگ اکٹھے ہوتے تو بیت بازی کیا کرتے تھے اور آخر میں والد صاحب اور دادی صاحبہ رہ جاتے تھے، باقی سب ہار جاتے تھے۔ مختلف علمی شخصیات سے متعلق سوالات پر مبنی ذہنی آزمائش کا کھیل ’کسوٹی‘ بھی بہت شوق سے کھیلتے تھے۔ ہم جب ان سے کہانی سننے کی فرمائش کرتے تو اسلامی تاریخ سے قصے سنایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت پسند تھا۔ وہ بہت زیادہ سناتے تھے۔
والد صاحب بہت خوش لباس بھی تھے۔ اپنے کپڑے بہت شوق سے سلواتے تھے۔ اگر کبھی ہم کہتے کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ کپڑے ہیں تو امام مالک بن انسؒ کا واقعہ سناتے کہ وہ روزانہ صبح کو نئے کپڑے پہنتے تھے اور جب کوئی ان سے اس کے بارے میں کہتا تو فرماتے تھے: ’نفعل ونستغفر‘ کہ ہم ایسا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔
اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انھوں نے کارآمد بنایا۔ شام کو جب چائے پیتے تھے تو ساتھ ساتھ کوئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ شام کو بلاناغہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ چاہے کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ کھانے سے پہلے چہل قدمی کے لیے جاتے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر گھر والوں کے ساتھ محفل سجایا کرتے تھے اور پھر رات کو بارہ ایک بجے تک اپنا کام کرتے تھے۔ آخری دن تک ان کا یہی معمول رہا۔
اپنا کام ہمیشہ خود کرتے تھے۔ کبھی کسی دوسرے کو زحمت نہیں دی۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنا بریف کیس ہمیشہ خود گاڑی میں رکھتے تھے، کبھی ڈرائیور کو نہیں دیا۔ آخری عمر میں بازو میں تکلیف رہنے لگی تھی اور بھاری چیز اٹھانے میں دقت ہوتی تھی، پھر بھی کبھی کبھار خود ہی اٹھا لیتے تھے۔ گاڑی میں سفر کے دوران میں ہمیشہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور اگر سفر لمبا ہوتا تو کوئی کتاب ساتھ رکھ لیتے تھے۔
طبیعت میں قناعت پسندی بہت زیادہ تھی۔ دنیاوی عیش وآرام سے بے نیاز رہتے تھے۔ اپنے بچپن کا قصہ سناتے تھے کہ ایک دفعہ میں پڑوسیوں کی گاڑی دیکھ کر بہت افسردہ ہوا کہ ان کے ٹھاٹھ باٹھ ہیں اور ہمارے نہیں ہیں۔ گھر آکر کہا کہ میں کل سے مدرسے نہیں جاؤں گا، مجھے بھی پڑوسیوں کے بچوں کی طرح اسکول جانا ہے۔ ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے۔ خوب روئے اور سو گئے۔ سو کر اٹھے تو دادی جان نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ چلو۔ وہ گھر کے قریب ہی مہاجروں کی جھونپڑیوں میں لے گئیں۔ کئی جھونپڑوں کے اندر لے کر گئیں اور پھر گھر آ کر خوب ڈانٹا کہ پڑوسیوں کے عیش وآرام تو تمھیں خوب نظر آئے، یہ لوگ نظر نہیں آتے کہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں! فرماتے تھے کہ انھوں نے ایسا سبق دیا تھا کہ میں دنیا کے بڑے سے بڑے محل میں گیا، خوب سے خوب تر ہوٹلوں میں ٹھہرا، مگر کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے۔ یہی بے نیازی اور تقویٰ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی عزت دی۔ ان کے ایک دوست نے کیا خوب کہا ہے کہ ایسا علم تو شاید دوبارہ پیدا ہو جائے، لیکن ایسا تقویٰ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے۔
واقعات تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن نہ الفاظ ساتھ دیتے ہیں اور نہ جذبات اجازت دیتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ان کے ادھورے رہ جانے والوں کاموں کو مکمل کرنے کی ہمت اور استطاعت عطا کرے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین
ایک معتمد فکری راہ نما
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کی اچانک خبر ملک بھر کے علمی وفکری حلقوں کی طرح میرے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ میں اس روز ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا۔ ایک روز قبل مولانا عبد الرؤف فاروقی اور مولانا قاری جمیل الرحمن اختر کے ہمراہ کلاچی گیا تھا۔ جمعیۃ علماء اسلام کے بزرگ راہ نما مولانا قاضی عبد اللطیف کی وفات کے بعد وہاں نہیں جا سکا تھا۔ ان کے برادر بزرگ حضرت مولانا قاضی عبد الکریم صاحب مدظلہ اور دیگر اہل خاندان سے تعزیت کی اور رات کو ہم ڈیرہ اسماعیل خان آ گئے۔ ڈیرہ میں موبائل فون کی سروس سکیورٹی کے عنوان سے ایک عرصے سے بند ہے۔ اپنے پروگراموں سے فارغ ہو کر دوپہر کے وقت ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے روانہ ہوئے تو شہر سے باہر نکلتے ہی موبائل فون کی گھنٹی بجی اور ہمارے گوجرانوالہ کے ساتھی حافظ محمد یحییٰ میر نے اطلاع دی کہ آپ کے اسلام آباد والے دوست ڈاکٹر محمود احمد غازی انتقال کر گئے ہیں۔ دل دھک سے رہ گیا۔ ان سے خبر کا ذریعہ پوچھا تو بتایا کہ ٹیلی وژن کے ایک چینل پر پٹی چل رہی ہے۔ اسلام آباد کے ایک دو دوستوں کو فون کیا تو انھوں نے تصدیق کر دی کہ ڈاکٹر صاحب کا صبح نماز فجر کے وقت انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جنازے کے بارے میں بتایا گیا کہ دو بجے اسلام آباد میں ہے۔ اس وقت ایک بجے دن کا وقت تھا۔ جنازے میں شریک نہ ہو سکنے کا صدمہ بھی ڈاکٹر غازی مرحوم کی اچانک جدائی کے غم کا ساتھی بن گیا۔
ڈاکٹر صاحب موصوف نے ۳؍ اکتوبر کو ہمارے ہاں گوجرانوالہ تشریف آوری کا پروگرام طے کر رکھا تھا۔ الشریعہ اکادمی میں ’’دینی مدارس میں تدریس قرآن کریم کی اہمیت اور تقاضے‘‘ کے موضوع پر ایک سیمینار کا پروگرام طے تھا جس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ تھے اور تاریخ انھی کے مشورے سے طے ہوئی تھی۔ ہم ا س سیمینار کی تیاری کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ مزید چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی ترتیب دے رہے تھے کہ اچانک انھیں مالک حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ سارے پروگرام چھوڑ کر داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
ڈاکٹر صاحب کا تعلق حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کے خاندان سے تھا۔ انھوں نے ابتدائی دینی تعلیم جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں حاصل کی اور دورۂ حدیث دار العلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی میں کیا۔ ان کے حدیث کے استاذ صوبہ خیبر پختون خواہ کے معروف محدث حضرت مولانا عبد الرحمن المینوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کے ترجمہ وتفسیر کے استاذ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ وہ اپنے استاذ محترم کی طرز پر مختلف یونیورسٹیوں میں چند روز کے اندر دورۂ تفسیر بھی کراتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے نوٹنگھم (برطانیہ) کے جامعہ الہدیٰ میں ملاقات ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ وہ لیسٹر کے ادارۂ اسلامک فاؤنڈیشن میں دس روزہ دورۂ تفسیر قرآن کریم کرانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو انھوں نے بتایا کہ وہ مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس طرز کے دورۂ تفسیر قرآن کریم کراتے رہتے ہیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں پیش رفت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر کے منصب پر فائز ہوئے، مگر ان کا اصل تعارف ان کی ڈگریوں کے حوالے سے نہیں، بلکہ ان کے علمی مقام اور دینی وعلمی خدمات کے حوالے سے جس نے انھیں دینی وعصری علوم کے ماہرین میں ایک متفق علیہ شخصیت اور معتمد راہ نما کے مقام پر فائز کر دیا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلی ملاقات یاد نہیں، مگر بیسیوں ملاقاتوں کے مناظر ذہن کی اسکرین پر جھلملا رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے ابتدائی دور میں ڈاکٹر غازی مرحوم ہماری دعوت پر گوجرانوالہ تشریف لائے۔ یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور تعلیمی نظام میں بہت سے مفید مشوروں سے نوازا۔ اس موقع پر انھوں نے جامع مسجد نور، مدرسہ نصرۃ العلوم میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے بھی خطاب کیا۔
ڈاکٹر صاحب مرحوم میرے علمی وفکری معاملات میں سب سے بڑے مشیر تھے اور ہمارے درمیان امت مسلمہ کے علمی وفکری مسائل پر تبادلہ خیالات او رمشاورت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ لندن میں مولانا محمد عیسیٰ منصوری اور مولانا مفتی برکت اللہ کے ساتھ مل کر ہم نے ’’ورلڈ اسلامک فورم‘‘ قائم کیا جو گزشتہ دو عشروں سے علمی وفکری محاذ پر سرگرم عمل ہے۔ فورم کا مقصد ملت اسلامیہ کو درپیش علمی وفکری مسائل کی نشان دہی اور ان کے حل کی تلاش میں کاوشوں کو منظم کرنا ہے۔ اس فورم کی تشکیل اور سرگرمیوں میں ہمیں جن نمایاں علمی شخصیتوں کا تعاون حاصل رہا ہے، ان میں مولانا عتیق الرحمن سنبھلی، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ڈاکٹر سید سلمان ندوی، مولانا سید سلمان الحسینی اور مولانا محمد عبد اللہ پٹیل کاپودروی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے ایک بار ہماری دعوت پر برطانیہ کا دورہ بھی کیا اور فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے علاوہ مختلف شہروں میں علمی اور فکری اجتماعات سے خطاب کیا۔
ورلڈ اسلامک فورم کی طرف سے ہم نے مغربی ممالک کے لیے اسلامی تعلیمات کے خط وکتابت کا سلسلہ شروع کرنا چاہا تو ہمیں دعوہ اکیڈمی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا کورس پسند آیا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب مرحوم دعوہ اکیڈیمی کے سربراہ تھے۔ انھوں نے نہ صرف بھرپور تعاون کیا، بلکہ باقاعدہ معاہدے کی صورت میں اردو اور انگلش نصابات کی کاپیاں فراہم کیں اور سالہا سال تک اس پروگرام کی سرپرستی کرتے رہے۔ یہ کورس جامعۃ الہدیٰ نوٹنگھم کے ذریعے کئی سال تک چلتا رہا ہے اور مختلف مغربی ممالک کے ہزاروں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے اور اب یہ ’’اسلامک ہوم اسٹڈی کورس‘‘ کے عنوان سے انٹر نیٹ پر موجود ہے اور سیکڑوں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ جن دنوں اس کورس کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کی جگہ دعوہ اکیڈمی کے نئے ڈائریکٹر جنرل کا تقرر ہو گیا۔ ہمیں بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارے مذاکرت چل رہے ہیں اور نئے آنے والے ڈائریکٹر جنرل کے مزاج سے ہم واقف نہیں ہیں، پتہ نہیں کہ وہ ہماری ضروریات کے مطابق تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میری برطانیہ کے سفر سے واپسی ہوئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے فون پر رابطہ کیا اور نئے آنے والے ڈائریکٹر جنرل کے حوالے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیں۔ میں اسلام آباد گیا اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ۔ انہوں نے مجھے ایک ڈرافٹ دیا اور کہا کہ اس پر دستخط کریں۔ ان دنوں میں ورلڈ اسلامک فورم کا چیئرمین تھا اور میرے وہاں دستخط ہونے تھے ۔ میں نے دستخط کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دعوہ اکیڈمی کا منصب چھوڑنے سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے اور مجھے یاد تھا کہ میں نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا ایک خوشگوار تجربہ تھا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں وزارت مذہبی امور کا منصب سنبھالا تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس میدان اور ذوق کے آدمی نہیں تھے، مگر رفتہ رفتہ ان کی حکمت عملی سمجھ میں آنے لگی تو میں ان کی ذہانت اور صلاحیتوں کا پہلے سے زیادہ معترف ہوتا گیا اور جب وہ وزارت سے الگ ہوئے تو میں اسلام آباد کے چند علماء کرام کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گیا۔ باتوں باتوں میں، میں نے انھیں مبارک باد پیش کی اور شکریہ ادا کیا تو وہ چونکے اورمیرے ساتھ جانے والے علماء کرام بھی متعجب ہوئے کہ میں شکریہ اور مبارک باد کس حوالے سے پیش کر رہا ہوں! میں نے عرض کیا کہ دینی مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کے لیے جنرل پرویز مشرف کا پروگرام طے پا چکا تھا اور اس پر عمل درآمد کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ڈاکٹر غازی مرحوم نے فائل ورک، پیپر ورک اور بیرونی دوروں کا جال بچھا دیا۔ مختلف مسلم ممالک کے تعلیمی نظاموں کا جائزہ لینے کے لیے وفود جانا شروع ہوئے اور ملک کے اندر مختلف حوالوں سے کمیٹیوں اور مذاکرات کا سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اتنے میں دینی مدارس کے مختلف وفاقوں کو اپنی صف بندی اور موقف وپالیسی میں یکسانیت پیدا کرنے کا موقع مل گیا اور وہ متحد ہو کر رائے عامہ کی قوت کے ساتھ سامنے آ گئے جس سے دینی مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کا پروگرام آگے نہ بڑھ سکا۔ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو اس کامیاب حکمت عملی پر مبارک باد دے رہا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر غازیؒ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ صرف آپ میری اس حکمت عملی کو سمجھ سکے ہیں، ورنہ اسلام آباد کے علماء کرام تو مجھے ابھی تک برا بھلا ہی کہہ رہے ہیں۔
وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے کچھ عرصہ قبل بڑے دینی مدارس میں تخصصات کے نصابات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنائی اور مجھے اس کا مسؤل بنایا تو میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب سے مشورہ ضروری سمجھا۔ انھوں نے نہ صرف متعدد مفید مشوروں سے نوازا، بلکہ ایک باقاعدہ رپورٹ دینی مدارس کے تخصصات کے بارے میں تحریر کی جو ماہنامہ ’الشریعہ‘ میں شائع ہو چکی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ اہم کام جو بتدریج آگے بڑھ رہا تھا، وفاق المدارس کی بیورو کریسی کی داخلی مصلحتوں اور ترجیحات کی نذر ہو کر معطل پڑا ہے۔
آخری ملاقات چند ماہ قبل اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی جب میں گوجرانوالہ میں شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے پراجیکٹ کے حوالے سے ان سے مشورے کے لیے گیا۔ ربع صدی قبل شروع کیا جانے والا ہمارا یہ پراجیکٹ مختلف وجوہ کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ زمین کا ایک بڑا رقبہ اور تین چار بلڈنگیں موجود تھیں۔ ہم دس پندرہ سال کے تعلیمی پروگرام میں اتار چڑھاؤ کے بعد یہ طے کر چکے تھے کہ اب مزید اس کام کو آگے بڑھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جن حضرات سے مشاورت ہوئی، ان میں ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ سرفہرست تھے۔ ہم ان کے پاس یہ تجویز لے کر گئے تھے کہ اگر یہ جگہ اور بلڈنگیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے کسی منصوبے میں کام آ سکتی ہوں تو وہ اس کے لیے ہماری مدد کریں۔ انھوں نے اس سے اتفاق کیا مگر کہا کہ پہلے کراچی کے کسی بڑے دینی ادارے سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ زیادہ بہتر رہیں گے۔ اگر وہاں بات نہ بن سکی تو پھر میں آپ حضرات کی تجویز پر پیش رفت کر سکتا ہوں۔ نام بھی انھوں نے انھوں نے تجویز کیا کہ اگر دار العلوم کراچی تیار ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، مگر وہ شاید ایسا نہ کریں، اس لیے جامعۃ الرشید سے بات کر لیں۔ وہ سنبھال بھی لیں گے اور بہتر انداز میں کوئی تعلیمی پروگرام بھی منظم کر لیں گے۔ یہ بات ایک آپشن کے طور پر ہمارے ذہن میں بھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی تائید سے پختہ ہو گئی۔ ہم نے جامعۃ الرشید سے بات کی اور انھوں نے جگہ اور بلڈنگیں سنبھال کر ’’جامعہ شاہ ولی اللہ‘‘ کے نام سے تعلیمی پروگرام کا آغاز گزشتہ سال شوال سے کر دیا ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی ڈاکٹر صاحب مرحوم کے صدقات جاریہ میں سے ہے اور اس تعلیمی پروگرام کے اجر وثواب میں وہ مسلسل شریک رہیں گے۔
اسی دوران ڈاکٹر صاحب مرحوم سے میری ایک ملاقات دار العلوم اسلامیہ کامران بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں دینی مدارس کے اساتذہ کے تربیتی پروگرام میں ہوئی جس میں مختلف امور پر باہمی تبادلہ خیالات ہوا۔ میرا بیان ظہر سے قبل ہو چکا تھا، مگر میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات اور ان کا خطاب سننے کے لیے مغرب تک رکا۔ اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان دونوں ملاقاتوں میں سے پہلے کون سی ہوئی اور دوسری کون سی، مگر یہ ہماری آخری دو ملاقاتیں ہیں جن کی یاد ہمیشہ ذہن میں تازہ رہے گی۔
ایک دفعہ خبر ملی کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور رات کے وقت ڈاکوؤں نے غازی صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزالی پر تشدد بھی کیا ہے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر ڈاکو کیا لینے آئے تھے۔ مجھے تو معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں کیا ہو گا۔ جب میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تو ان سے معاملہ دریافت کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ! ان کو کس طرح حوصلہ ملا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز مل سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اصل میں ان ڈاکوؤں کو مغالطہ لگ گیا ۔ وہ اس طرح کہ جب بھی مجھے کسی دوسرے ملک میں کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی تحفہ یا اعزاز ملتا ہے اور وہ جن ڈبوں میں بند ہوتے ہیں، وہ زیورات کے ڈبوں کی طرح سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میرے گھر میں ڈھیروں پڑے ہوئے ہیں اور تین چار الماریاں بھری پڑی ہیں۔ کسی آنے جانے والے کو مغالطہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اتنا زیور ہے۔ وہ مغالطہ ڈاکووں کو یہاں لے آیا اور بے چارے غزالی پر تشدد کر کے چلے گئے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کو عام طور پر یونیورسٹی کی دنیا کا آدمی سمجھا جاتا رہا ہے، حالانکہ وہ اصلاً دینی مدارس کے ماحول کے آدمی تھے اور جدید تعلیم کی دنیا میں روایتی دینی حلقوں کی بھرپور اور کامیاب نمائندگی کر رہے تھے۔ جدید ماحول میں آج کے اسلوب اور اصطلاحات میں دین اسلام اور امت مسلمہ کے روایتی اور اجماعی موقف کے جس کامیابی اور اعتماد کے ساتھ وہ نمائندگی کرتے تھے، مجھے اس معاملے میں اس حوالے سے بلا مبالغہ ان کا کوئی ثانی دکھائی نہیں دے رہا۔ علمی محاذ پر بہت سی شخصیات ان پر تفوق رکھتی ہیں، لیکن علم کے صحیح اور بروقت استعمال اور علم وفکر میں توازن کے حوالے سے وہ اپنے معاصرین میں سب سے نمایاں تھے۔ ڈاکٹر صاحب دینی اور عصری علوم پر یکساں دسترس رکھتے تھے۔ عربی اور انگلش سمیت نصف درجن کے لگ بھگ زبانوں میں قادر الکلام تھے اور تحریر وتقریر پر ان کی مکمل دسترس تھی۔ بے پناہ مطالعہ اور تجزیہ وتنقیح کی اعلیٰ صلاحیت سے بہرہ ور تھے۔ مشکل سے مشکل مسئلہ کی گہرائی تک اترتے اور اس کا قابل عمل حل نکالتے تھے۔ نامساعد حالات میں بھی اعتماد اور خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرنے اور اپنا کام کر گزرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ بین الاقوامی کانفرنسوں میں اسلام کی نمائندگی اور جمہور اہل علم کے موقف کی ترجمانی کے لیے پوری دنیاے اسلام میں گنتی کے جن چند حضرات کا نام لیا جا سکتا تھا، ان میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر محمود احمد غازی کا بھی تھا۔ کسی سطح کی کانفرنس ہو اور کوئی بھی موضوع ہو، وہ پورے اعتماد، حوصلے اور جرات کے ساتھ اسلام کی ترجمانی کرتے تھے اور مطالعہ اور گفتگو کے عصری اسلوب پر ان کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ فکر ودانش کی کوئی بھی سطح اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی۔
ڈاکٹر غازی مرحوم کے علمی تبحر، مطالعہ کی وسعت اور دینی وعصری تقاضوں کے مکمل ادراک کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ موقع ومحل کے مطابق محفل کی ذہنی سطح کا لحاظ کرتے ہوئے موثر اور ثمر آور گفتگو کی صلاحیت تھی اور اس کے علاوہ ان کی سادگی، انکساری اور درویش مزاجی تھی جو ان کے حلقہ احباب میں ان کی مقبولیت کا باعث تھی۔ میرا احساس ہے کہ وہ اپنی علمی سطح اور منصبی مقام کو سامنے رکھتے ہوئے پروٹوکول کے تکلف میں پڑے رہتے تو شاید اتنے زیادہ لوگ ان سے علمی استفادہ نہ کر پاتے۔ میرے خیال میں پروٹوکول کا تکلف علمی دنیا میں استفادہ اور افادہ دونوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور میں اس سلسلے میں امام ابویوسفؒ کے اس قول کا اکثر حوالہ دیا کرتا ہوں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک غریب اور معمولی خاندان کا فرد ہوتے ہوئے علم وفضل کے اس قدر بلند مقام تک کیسے پہنچے ہیں تو فرمایا کہ:
ما استنکرت من الاستفادۃ وما بخلت بالافادۃ
میں اس کا اپنی زبان میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں کہ :
’’علم کے حصول اور فروغ میں میرا کبھی کوئی پروٹوکول نہیں رہا۔‘‘
میں نے ڈاکٹر غازی مرحوم کو حضرت امام ابو یوسفؒ کے اس ارشاد کا عملی مصداق پایا ہے اور کم وبیش دو عشروں تک اس کامشاہدہ کرتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے ساتھ میرا تعلق مخلص بھائیوں اور بے تکلف دوستوں والا تھا۔ انھوں نے ہمیشہ مجھے بڑے بھائی کا احترام دیا اور میرے لیے ہمیشہ وہ سب سے زیادہ معتمد اور مخلص مشیر ثابت ہوئے۔ وہ اپنی زندگی پوری وضع داری کے ساتھ گزار کر چل دیے ہیں اور بارگاہ ایزدی میں ان کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ رات کو ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ فجر تک ہسپتال میں رہے، فجر کے وقت ہوش میں آئے تو نماز کا وقت پوچھا اور یہ معلوم کر کے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز فجر ادا کی اور اس کے چند لمحوں بعد جان جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ رسم ومحاورہ کی بات نہیں، بلکہ امر واقعہ ہے کہ ہم اپنے دور کی ایک بڑی علمی شخصیت اور معتمد فکری راہ نما سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول فرمائیں، سیئات سے درگزر کریں، آخرت کی منزلیں آسان فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں۔ آمین یا رب العالمین۔
ایک عظیم اسکالر اور رہنما
مولانا محمد عیسٰی منصوری
ڈاکٹر محمود احمد غازی کی ہستی برصغیر کے ا ہل علم میں ایک ایسی شخصیت تھی جو بین الاقوامی مجالس وکانفرنسوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر اسلام اور جمہور اہل علم کی ترجمانی کرتی تھی۔ بقول مولانا زاہدالراشدی کے ’’مکالمے اور گفتگو کے عصری اسلوب پر ان کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ فکر ودانش کی کوئی بھی سطح اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی۔‘‘ انہوں نے خاموشی سے جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر پرویز مشرف کے دور تک بعض ظاہر بین لوگوں کی ملامت کی پروا کیے بغیر حکومتی سطح پر وہ کام کر دکھایا جو صرف آپ ہی کے کرنے کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جنرل ضیاء الحق کے عربی کے ترجمان اور دینی معاملات میں مشیر بن کر بہت قریب تھے۔ آپ نے خاموشی سے جنرل ضیاء الحق سے حکومتی سطح پر متعدد دینی وعلمی کام کروائے، خواہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا خاکہ ہو، خواہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی دعوۃ اکیڈمی وشریعہ اکیڈمی کے ذریعے بے شمار دینی وعلمی کتب کی طباعت اور دنیا بھر میں ایسے ممالک میں اسلامی اسکالرز تیار کرنا جہاں مسلمان اقلیت میں اور غیر اسلامی تمدن وکلچر کے دباؤ میں ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی کی طرف سے متعدد دینی واسلامی کورسز کا اجرا جس کے ذریعے ہزار ہا طلبہ نے مطالعہ اسلام، مطالعہ قرآن اور متعدد کورس کیے۔ خود برطانیہ میں ڈاکٹر صاحب کے عطا کردہ مطالعہ اسلام کا دو سالہ کورس (ہوم اسٹڈی کورس) ورلڈ اسلامک فورم کے توسط سے تقریباً دس ہزار طلبہ وطالبات نے کیا۔ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر ونائب صدر رہے اور حقیقت یہ ہے کہ یونیورسٹی کی دعوۃ اکیڈمی وشریعہ اکیڈمی کی خاکہ گری کرنے والوں میں سب سے نمایاں اور عرصہ تک ان دونوں اکیڈیمیز کی روح رواں آپ ہی کی شخصیت تھی۔
اسی طرح سود کے خلاف سپریم کورٹ کے مشہور اور تاریخ ساز فیصلہ میں ڈاکٹر صاحب کا بحیثیت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے نمایاں کردار رہا ہے۔ اس مشہور فیصلے کا بڑا حصہ ڈاکٹر صاحب ہی کا تحریر کردہ ہے، اگرچہ پاکستان کے متعدد علماء کرام اورجج صاحبان اس میں شامل تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ (پیرس) کے بعد برصغیر میں آئینی وقانونی معاملات میں آپ اسلامی دفعات کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہؒ کے مشہور خطبات بہاولپور کی دوسری جلد جو قانون بین الممالک کی موضوع پرہی ہے، وہ ڈاکٹر غازی صاحب ہی کے محاضرات ہیں۔ اس کامطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کی نظر قانون بین الممالک یا انٹرنیشنل لا پر اپنے پیش رو سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اسی طرح بہت کم لوگوں اس حقیقت کا علم ہے کہ برصغیر میں آپ اسلامی بینکنگ کے بانیوں میں تھے۔ اسلامی بینکنگ کے لیے تکافل کا ابتدائی خاکہ آپ ہی کا تشکیل کر دہ ہے۔ اس پر پاکستان سے بہت پہلے بعض عرب ممالک اور ملائیشیا میں عمل ہوا۔ اسلامی معاشیات پر آپ کا علمی وفکری اور تجدیدی کام بہت وقیع اور ناقابل فراموش ہے اور آخر تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ ایڈوائزی بورڈ کے چیئرمین کامنصب آپ ہی کے پاس تھا۔
اسی طرح قادیانیوں کے خلاف امت مسلمہ کے متفقہ موقف کی ترویج واشاعت اور اس سلسلے میں ہونے والی قانون سازی میں ڈاکٹر صاحب کی تگ ودو اور ماہرانہ رائے کا بڑا دخل رہا ہے۔ ۸۰ء کی دہائی میں ساؤتھ افریقہ میں قاد یانیوں کے متعلق مقدمہ میں صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم نے پاکستان کے جید علماء کرام اور ماہرین قانون کا ایک موقر اور اعلیٰ سطحی وفد روانہ کیا تھا۔ وہاں عدالت عالیہ کے سامنے امت مسلمہ کا موقف پیش کرنے کی سعادت ڈاکٹر صاحب ہی کے حصے میں آئی۔ بالآخر اسی تاریخی مقدمے میں ملت اسلامیہ کے موقف کو غیر مسلم عدالت کے سامنے سرخروئی حاصل ہوئی۔ آج یہ فیصلہ دنیا بھر کے غیر مسلم ممالک کی عدالتوں کے لیے ایک نظیرہے۔ ایک بار بندہ نے ابراہیم کالج لندن میں برطانیہ کی مختلف ختم نبوت تنظیموں کے سربراہوں اور علماء کو بلا کر ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ کروائی۔ ان علماء کرام کے روبرو ڈاکٹر صاحب نے جو بصیرت افروز تقریر فرمائی، بندہ نے اس مسئلہ پر ایسی ٹھوس اور مدلل تقریر کبھی نہیں سنی تھی۔ آج بھی آپ قادیانیوں کی ویب سائٹ کھولیں تو اندازہ ہوگا کہ قادیانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ڈاکٹر صاحب ہی سے تھی۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی پرویز مشرف کی تشکیل کردہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا حصہ بنے تو بعض بزرگوں نے آپ کو لعنت ملامت کا نشانہ بنایا۔ بندہ نے اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک ممتاز ترین عالم دین سے ڈاکٹر صاحب کے متعلق سخت ترین الفاظ سنے۔ ان بزرگ نے مجھے بتایا کہ میں نے بھرے مجمع میں ڈاکٹر صاحب کو کھری کھری سنائیں۔ بندہ نے دل میں کہا کہ یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب کا حوصلہ، شرافت اورکمال ہے کہ آپ کے منصب کا لحاظ کر کے خاموش رہے، لیکن اہل نظر خوب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مشرف جیسے شخص کے ساتھ رہ کر بھی جو کام انجام دیا، وہ صرف انھی کے کرنے کا تھا۔ چنانچہ رفیق محترم مولانا زاہدالراشدی صاحب لکھتے ہیں:
’’میں ان کی صلاحیتوں اور افتاد طبع سے آگاہ تھا، اس لیے کوئی تشویش نہیں تھی اور میں خاموشی سے ان کے ’’اپنا کام کر گزرنے‘‘ کی صلاحیت کا مشاہدہ کرتا رہا، چنانچہ جب مشرف نے آپ کو وزارت سے فارغ کر دیا تو میں اسلام آباد کے بعض علماء کرام کے ہمراہ ان سے ملنے گیا اور مبارک باد دینے کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کیاتو دوستوں کو تعجب ہوا کہ میں شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ دینی مدارس کے خلاف پرویز مشرف کی پرجوش پالیسی کی شدت کو جس حکمت عملی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کم کیا ہے اور اس پالیسی کو ٹالنے کے لیے داؤ پیچ ڈاکٹر صاحب نے کھیلے ہیں، یہ انھی کا کام تھا۔ ان خطرناک حالات میں امریکہ نے پرویز مشرف کے ذریعے دینی مدارس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے ہلہ بول دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی حکمت عملی یہ تھی کہ پیپر ورک، فائل ورک اور مسلمان ملکوں کے تعلیمی نظاموں کا جائزہ لینے کے حوالوں سے سرکاری وفود کا سلسلہ دراز کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران دینی مدارس کے وفاقوں کو باہمی رابطوں اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کاموقع مل گیا اور انہوں نے مشترکہ موقف طے کر کے حکومتی پالیسی کی مضبوط مزاحمت کا راستہ اختیار کر کے حکومت کی پالیسی کو ناکام بنا دیا۔‘‘
برصغیر میں ڈاکٹر حمیداللہ (پیرس) کے بعد ڈاکٹر محمود احمد غازی ایسے شخص تھے جو اردو، عربی، فارسی، انگریزی، فرنچ سمیت چھ سات زبانوں کے ماہر اور ان زبانوں میں اعلیٰ تحقیق وتصنیف وخطابت کا ملکہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ ؒ کی فرانسیسی زبان میں دو جلدوں پر مشتمل سیرت کی شہرہ آفاق کتاب کا ڈاکٹر صاحب نے براہ راست فرنچ سے انگریزی میں ترجمہ کیا جو بہت مقبول ہوا۔ اسی طرح آپ کی آخری تصنیف ’’الحرکۃ المجددیہ‘‘ جو عربی میں چار سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، برصغیر کی عبقری شخصیت حضرت مجدد الف ثانیؒ کے احوال و آثار اور خدمات وتصنیفات کے علمی جائزے پر ہے۔ یہ کتاب آپ کی فارسی وعربی دانی کے ساتھ علمی تبحر اور تصوف کے دقائق سے گہری واقفیت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح قرآن، حدیث، سیرت، فقہ، شریعت اور معیشت وتجارت پر آپ کے محاضرات علوم اسلامیہ کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ پورے اسلامی کتب خانہ میں ان محاضرات کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ان محاضرات کو پڑھنے والا ڈاکٹر صاحب کی وسعت علمی، وفور معلومات، ذہانت وقوت یادداشت اور قرآن وسنت اور تاریخ پر گہری بصیرت پر عش عش کر اٹھتا ہے۔ بندہ ورلڈ اسلامک فورم کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے محاضرات کی ان چھ جلدوں کو ورلڈ اسلامک فورم کی طرف سے لیسٹر کے دارارقم کے تعاون سے انگریزی میں چھاپا جائے گا۔ الحمد للہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔
اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے گوجرانوالہ (پاکستان) کی الشریعہ اکادمی کی ایک فکری نشست میں مسلمانوں کے نظام ونصاب تعلیم پر جو مبسوط خطاب فرمایا تھا، وہ اس موضوع پر ’’ما قل ودل‘‘ کی بہترین مثال ہے۔ اس میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ مولانا ر اشدی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی فکری نشستوں کو مرتب کر کے چھاپ دیا ہے جو علماء کرام کے لیے نادر تحفہ ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عزیز الرحمن چند برس پہلے جامعۃ الرشید کراچی میں قضاء وتحکیم کے موضوع پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کے قضا کی پوری روایت اور اس کا محاکمہ ایسے انوکھے اسلوب میں پیش فرمایا کہ ملک بھر کے مفتیان کرام حیرت زدہ رہ گئے اور سب نے متفقہ طور پر اس خطاب کو پورے کورس کا حاصل قرار دے دیا۔ بندہ کے نزدیک ڈاکٹر صاحب طبقہ علماء میں برصغیر کی منفرد شخصیت تھے جو مشکل سے مشکل موضوع پر برجستہ اور مدلل خطاب کی صلاحیت سے بہرہ ور تھے۔ ایک بار لندن کے مشہور کانوے ہال واقع ہالبرن میں بندہ نے اسلامائزیشن کے موضوع پر خطاب کی دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام میں اس موضوع پر ہونے والی کوششوں کی مکمل تاریخ پیش فرما دی۔
نومبر ۱۹۹۲ء میں رفیق محترم مولانا زاہدالراشدی اور بندہ نے یہاں برطانیہ میں مغربی فکر وفلسفہ کا جائزہ لینے اور اس کے موثر جواب کے لیے ورلڈ اسلامک فورم تشکیل دیا۔ اس وقت ہم نے ایک اعلیٰ سطحی مشاورتی حلقہ بنایا جس میں ڈاکٹر سلمان ندوی (ساؤتھ افریقہ)، مولانا سید سلمان الحسینی (لکھنو)، مولانا مجاہدالاسلام قاسمی (بھارت)، مولانامحی الدین خان (ڈھاکہ) اور پاکستان سے ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمارے شریک فکر اور شریک کار تھے۔ یوں تو ڈاکٹر صاحب کی برطانیہ متعدد بار تشریف آوری ہوئی۔ فورم کی دعوت پر ۱۹۹۴ء میں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر سلمان ندوی (ساؤتھ افریقہ) اورجناب صلاح الدین شہید مدیر تکبیر نے ہمارے ساتھ برطانیہ کے مختلف شہروں کا دورہ فرمایا۔ مختلف شہروں کی علمی تقریبات اور سیمیناروں میں شرکت فرمائی جن کی یادیں آج بھی یہاں کے علما اور دینی کارکنوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ اسی طرح فورم نے برطا نیہ میں ’’اسلامک ہوم اسٹڈی کورس‘‘ کے عنوان سے بذریعہ خط وکتابت اسلامی کورس شروع کیا تھا جس کے انچارج مولانا رضاء الحق آف نوٹنگھم تھے اور اس میں مولانا مشفق الدین بھی عملی طو ر پر شریک رہے۔ اس کورس سے برطانیہ میں ہزارہا طلبہ اور طالبات نے فائدہ اٹھایا ۔ اس کورس کی عملی رہنمائی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی تھی۔ اس وقت آپ بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد کی دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے۔ ہم نے دعوۃ اکیڈمی کا یہ کورس ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کی صورت میں شروع کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب مسلسل اس کی رہنمائی اور سرپرستی فرماتے رہے۔
جہاں تک یاد پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے بندہ کی پہلی ملاقات غالباً ۱۹۸۴ء میں پاکستان کے پہلے سفر کے موقع پر ہوئی۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب اسلامی یونیورسٹی کی دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے۔ آپ نے ایک اجنبی زائر کے لیے اپنی قیمتی مصروفیات سے کئی گھنٹے فارغ کر کے ملاقات فرمائی۔ اس وقت بندہ کا احساس تھا کہ ایک ایسی شخصیت مل گئی جو فورم کے مقاصد میں بین الاقوامی سطح پر ہماری سرپرستی ورہنمائی کرسکتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے تعلق گہرا ہوتا گیا۔ جب بھی پاکستان کا سفر ہوتا، سب سے زیادہ اشتیاق ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا ہوتا کیونکہ پاکستان کے اہل علم میں آپ کی شخصیت ایسی ہستی تھی جن کی عالمی حالات پر گہری نظر تھی۔ خاص طور پر مغربی دجالی طاقتوں کے طریقہ واردات، پالیسیوں اور اقدامات میں آپ کو گہری بصیرت حاصل تھی۔ آپ سے مل کر کئی ذہنی وفکری گتھیاں سلجھ جاتیں۔ ڈاکٹر صاحب کی رہائش گاہ پر بھی نشستیں ہوتیں اور ہم آپ کی رفاقت سے مستفید ہوتے۔ پاکستان کے آخری سفر میں برطانیہ کے چھ علماء ہمراہ تھے جن میں مولانا مشفق الدین، مولانا شمس الضحیٰ اور مولانا فاروق ملا بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے طویل ملاقات اور مشورے رہے۔
بین الاقوامی فورم پر اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کا جو سلیقہ ڈاکٹر صاحب کو تھا، اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ آپ علم وفضل، دینی حمیت وتصلب کے ساتھ ساتھ حسن تکلم وحکمت کی دولت سے آراستہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب حکومت کے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز رہے۔ آپ وفاقی وزیر بر ائے مذہبی امور، ممبر پاکستان سیکورٹی کونسل، جج وفاقی شرعی عدالت، چیئرمین شریعہ ایڈوائزری بورڈ برائے اسٹیٹ بینک آپ پاکستان، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے صدر، نائب صدر، ڈائریکٹر دعوۃ اکیڈمی وغیرہ وغیرہ رہے، مگر کبھی سرکاری مراعات سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ کا علمی مقام یہ تھا کہ بیسیویں صدی کی عبقری شخصیت ڈاکٹر حمیداللہ آف پیرس نے ایک بار ڈاکٹر صاحب کو خط میں تحریر فرمایا کہ آپ کو میری کتب اور تحریروں میں حک واضافہ کا اختیار ہے۔ آپ کو تصوف واحسان میں برصغیر کے تین چار اہم ترین اکابر کی طرف سے اجازت بھی حاصل تھی، مگر آپ نے اس طرح اخفا سے کام لیا کہ گنتی کے چند افراد ہی واقف ہو ں گے۔ آپ سماع حدیث کی متعدد اعلیٰ ترین سندیں رکھتے تھے ۔ ایک سند ایسی تھی جو صرف چار واسطوں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تک پہنچ جاتی ہے۔
آپ کی گفتگو بڑی پر حکمت اور دانائی کی ہوتی۔ ایک بار ملائیشیا میں بین الاقوامی یونیورسٹی کی ورک شاپ کے موقع پر فرمایا کہ آج کے دور میں کوئی اگر خلیفہ ، وزیر، ا میر یا کسی منصب پر پہنچ جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں عبداللہ بھی ہوں۔ ایک بار ہم آکسفورڈ میں اسلامی سنٹر کے ڈائریکٹر فرحان نظامی سے ملنے گئے تو وہاں عرب شہزادوں کی داد ودہش کا تذکرہ تھا جو مغربی ممالک میں نام ونمود کی جگہوں پر علم اور اسلام کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور بڑے فراخ دل واقع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عربوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے سرپرست رہنا چاہتے ہیں، خادم نہیں۔ آپ ہمیشہ خود کو ایک دنیا دار شخص ظاہر کرتے، مگر بندہ نے ہمیشہ آپ کو کسی علمی مشغولیت (مطالعہ وتصنیف) میں دیکھا یا ذکر وتلاوت میں۔ ایک بار برطانیہ کے شہر لیسٹر میں مولانا فاروق ملا کے سنٹر دارارقم میں ایک ہفتہ تک ڈاکٹر صاحب کے محاضرات رہے۔ فقہ الاقلیات جیسے نادر موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی قدرت کلام اور حسن خطابت دیکھ کر بار بار دل تڑپتا کہ کاش! برطانیہ کے مولوی صاحبان جبہ ودستار اورالقاب کے پھندوں سے نکل کر اس گوہر نایاب کی قدر کر کے فائدہ اٹھاتے۔ ڈاکٹر صاحب کی خداداد صلاحیتوں سے تقریباً دو سال ملائیشیا کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اور تقریباً اتنی ہی مدت عربوں میں قائم ہونے والی سب سے اعلیٰ معیار کی بین الاقوامی یونیورسٹی آف قطر نے استفادہ کیا۔ بندہ نے گزشتہ سال اپنے مخلص دوست مولانا رفیق ندوی کی، جو قطر میں مقیم ہیں، ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہر ہفتہ کسی خاص موضوع پر ڈاکٹر صاحب کا لیکچر رکھیں اور ان کی ڈی وی ڈی تیار کر کے ہمیں فراہم کریں۔ ورلڈ اسلامک فورم کی طرف سے ایک معیاری دعوتی چینل قائم کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ اسے تین سال پہلے دی میسیج کے نام سے رجسٹرڈ کروا لیا گیا تھا۔ جناب کامران رعد صاحب اس کے انچارج ہیں جو تن دہی سے اپنے کام میں جتے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہاں برطانیہ میں گزشتہ چند سالوں میں درجن بھر شیعہ، سنی، بریلوی، سلفی، دیوبندی چینل کھل گئے ہیں، مگر ان میں نہ انسانیت کے لیے کوئی پیغام ودعوت ہے نہ مسلمانوں کے لیے مقصد حیات اور امت پنے کا پیغام، نہ آج کے تہذیبی، فکری ونظریاتی چیلنجز کا جواب۔ یہ سات چینل محض اپنے اپنے مسلک کی اشاعت اور اپنے اکابر کی ثنا وتوصیف اور کہانیوں کے لیے وقف ہیں۔ خدا کرے ہم جلد اس قابل ہو سکیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطابات اپنے چینل سے نشر کر سکیں۔
ڈاکٹر صاحب کے اخلاص اوراپنی ذات کے اخفا کا یہ عالم تھا کہ فورم کی طرف سے ۱۶؍ اکتوبر ۲۰۱۰ء کو ڈاکٹر صاحب کے لیے تعزیتی اجلاس کے موقع پر جب صدارتی خطبہ کی تیاری کا مرحلہ آیا تو خیال آیا گھر میں ڈاکٹر صاحب کی درجن بھر تصانیف ہیں۔ آپ کی شخصیت واحوال پر مضمون تیار کرنے میں ان سے مدد مل جائے گی۔ جب کتب اٹھا کر دیکھیں تو ان میں ایک لفظ ڈاکٹر صاحب کی ذات سے متعلق نہیں ملا۔ اس دور میں لوگ چھوٹی چھوٹی کتب مرتب کر کے اکابر کی تقریظ ومقدمہ کے نام سے اپنا پورے حالات زندگی بڑھا چڑھا کر لکھوا لیتے ہیں۔ بندہ نے ڈاکٹر صاحب کی طرح سفر وحضر میں تلاوت قرآن اور اذکار ومعمولات کی پابندی کرنے والے بہت کم دیکھے۔ آپ عام طور پر باوضو رہتے، فارغ اوقات میں اور دوران سفر اکثرآپ کے لبوں پر تلاوت قرآن جاری رہتی۔ آپ حافظ قرآن تھے، رمضان المبارک میں اپنی رہائش گاہ پر تراویح میں قرآن سنانے کا معمول تھا۔ آپ سادگی، تواضع اور انکسار کی تصویر تھے۔ جو کھانا سامنے رکھ دیا جاتا، انتہائی رغبت سے تناول فرماتے۔ ایک بار بندہ نے کہا کہ علماء کے مجمع میں خطاب کرنا ہے۔ برطانیہ کے مولوی صاحبان کی ظاہرپرستی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ آپ شلوار قمیص پہن کر چلیں تو اچھا ہے۔ فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں جو ہوں وہ ہوں۔ حالانکہ اکثر اوقات شلوار قمیص ہی میں رہتے۔ ایک بار مولوی فاروق ملا تقریباً ڈیڑھ دو سو میل کا سفر کر کے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عابد اور غازی آف شکاگو اور بندہ کو برطانیہ کے ایک قابل دید تفریحی مقام پر لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے سیر وتفریح یا تاریخی مقامات دیکھنے سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ کہنے لگے کہ سارے پہاڑ، سمندر، دریا ایک ہی جیسے تو ہوتے ہیں۔ غرض آپ سادگی اور خوبیوں کا مجموعہ تھے۔
۲۶؍ ستمبر ۲۰۱۰ء کو صبح کی نماز کے بعد تقریباً سات بجے اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اسلام آباد سے غالباً ڈاکٹر صاحب کے بھائی ڈاکٹر غزالی یا کوئی عزیز خبر دے رہے تھے کہ اچانک حرکت قلب بند ہونے سے ڈاکٹر صاحب انتقال کر گئے، اناللہ وانا الیہ راجعون۔ بند ہ سن کر سکتے میں رہ گیا۔ ایسا محسوس ہو اکہ سب کچھ تباہ ہو گیا ۔ نظریاتی وفکری کام کرنے والوں کے لیے کتنا عظیم سانحہ ہے۔ اکتوبر ۲۰۱۰ء کے آخری عشرہ میں ہم لوگوں نے مولانا سلمان الحسینی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا برطانیہ کا دورہ طے کیا۔ خیال تھا کہ طویل عرصہ کے بعدڈاکٹر صاحب سے دل کھول کر باتیں ہوں گی، مغرب اور ملت اسلامیہ کے احوال اور درپیش مسائل پر غور وخوض کر کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کریں گے مگر
اے بسا آرزو کہ خاک شدہ
واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے دور کی ایک بڑی علمی شخصیت اور فکری رہنما سے محروم ہو گئے ہیں۔ عرصہ سے ہم دیوبندیوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ظاہرپرستی کا شکار ہیں، ظاہری ہیئت، جبہ ودستار اور بڑے بڑے رسمی القاب میں الجھ کر بہت سے قابل قدر لوگوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ جب ڈاکٹر حمیداللہ کا انتقال ہوا اور بندہ نے ڈیلی جنگ میں آپ پر تفصیلی مضمون لکھا تو ایک مولوی صاحب نے فون پر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کس کے خلیفہ تھے؟ میرا جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلیفہ تھے۔ بہت سے مولوی صاحبان کے فون آئے کہ آپ نے پہلے نہیں بتایا ورنہ ہم فرانس جا کر استفادہ کرتے۔ میں نے کہا، آپ کبھی استفادہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ظاہر پرستی کے مرض کا شکار ہیں۔ وہ ایک سادہ سے مسلمان تھے، کوئی پیر یا مولوی نہیں تھے۔ اسی طرح ہمارا طبقہ ڈاکٹر غازی سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ ہم نے کتنی عظیم شخصیت کھو دی۔ ڈاکٹر صاحب کا وجود عالم اسلام کے لیے غنیمت تھا۔ آپ کو دیکھ کر ملت کی بے مایگی وبے بضاعتی کا احساس کم ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے اور ملت اسلامیہ کو ڈاکٹر صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم
محمد موسی بھٹو
(۱)
ملک کے ممتاز فاضل، دانشور اور محقق ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ساٹھ سال کی عمر میں ۲۶ ستمبر کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ’’اناﷲ وانا الیہ راجعون‘‘۔ ہمارے حلقہ سے وابستہ علمی دوستوں وساتھیوں کی، ایک ایک کرکے جدائی جہاں دلی صدمہ کا باعث ہے، وہاں موت کی تیاری کے لیے انتباہ کی حیثیت کی حامل بھی ہے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، جدید نوعیت کے فقہی مسائل میں ماہرانہ صلاحیتوں کے حامل تھے، کئی زبانوں میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی بڑی حیثیت یہ تھی کہ وہ دردمند داعی تھے اور خدمت اسلام کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔ عالم اسلام کے حالات ومسائل اور جدید معاشروں کی معاشی ومعاشرتی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کے حل کے سلسلہ میں وہ وسیع معلومات رکھنے کے ساتھ ساتھ حد درجہ خود اعتمادی کے حامل بھی تھے۔
محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب بنیادی طور پر دینی مدرسہ کے فارغ تھے۔ ان کا آبائی وطن مولانا اشرف علی تھانوی کا قصبہ تھانہ بھون ہے۔ موصوف کے والد صاحب قرآن کے حافظ اور عالم دین تھے۔ وہ مولانا اشرف علی تھانوی ؒ سے بیعت تھے۔ انہیں چشتی سلسلہ میں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ؒ سے خلافت حاصل تھی۔ محترم غازی صاحب خود مولانا عبدالقادر رائے پوری سے بیعت تھے۔ یہ ساری تفصیل موصوف کے اس عاجز کے نام ان خطوط میں موجود ہے جو مضمون کے آخر میں شامل ہیں۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اہم عہدوں پر فائز رہے۔ دعوہ اکیڈمی کے سربراہ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی کے سربراہ، وفاقی شرعی عدالت کے جج اور وفاقی حکومت کے وزیر وغیرہ۔ یہ سارے عہدے ان کے مزاج کی انکساری کو متاثر نہ کر سکے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو پختہ باطنی تربیت کا ثمرہ ہے۔ موصوف نے اپنے نام کے ساتھ کبھی ڈاکٹر کا لاحقہ نہیں لگایا۔ ان کی کسی کتاب میں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، حالانکہ ڈاکٹر بن جانے کے بعد افراد کی عام طور پر یہی آرزو رہتی ہے کہ ان کی طرف ڈاکٹر کی صفت منسوب کی جائے، اس طرح اسے خوبصورت اعزاز سے نوازا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اندر بدل جاتا ہے تو اس طرح کی آرزوئیں کالعدم ہوجاتی ہیں اور فرد فقیرانہ صفات کا حامل ہوجاتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے وہ خوشی ولذت محسوس کرنے لگتا ہے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے بھی نوازا تھا کہ وہ بڑے سے بڑے دشوار موضوع پر نوٹس لیے بغیر تقریر کرتے تھے اور تقریر میں واقعات کی صحت اور حقیقت کی صحیح عکاسی دیکھ کر ان کے غیرمعمولی حافظہ پر حیرت ہوتی تھی۔ ان کی بیشتر کتابیں ان کی تقاریر کے مجموعہ پر مشتمل ہیں۔ خالص فنی، واقعاتی اور تاریخی معلومات پر مشتمل تقاریر میں اس طرح کی صحت بیانی فیضان خاص ہے جس کا کچھ حصہ محترم غازی صاحب کو دیا گیا تھا۔ غازی صاحب نے اس خداداد صلاحیت سے استفادہ کرتے ہوئے تقاریر کے ذریعہ خدمت اسلام کا بڑا فریضہ سرانجام دیا۔ اگرچہ ان کی تقاریر بہت سارے موضوعات کا احاطہ کرتی تھیں، لیکن تدوین، حدیث، تدوین فقہ، دور جدید میں نفاذ اسلام کی شکل، اسلام کا قانونی نظام، اسلام کا بین الاقوامی نظام، جدید پیچیدہ مسائل کے سلسلہ میں صحیح اسلامی تعلیمات کی توضیح، مسلم معاشروں کو طاقتور مادہ پرست معاشروں کی طرف سے چیلنج وخطرات اور ان کی گہری سازشوں کی نشاندہی اور ان سے عہدہ برآہونے کی صورت جیسے موضوعات ان کی تقاریر کا خصوصی اہداف تھے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ پاکستان کے اعلیٰ علمی اداروں میں اسلام کی بہتر اور مؤثر طور پر ترجمانی کرنے میں ڈاکٹر صاحب کو خصوصی امتیاز حاصل تھا۔ ان کے انتقال سے اس میدان میں جو خلا پیدا ہو ہے، بظاہر اس کے پر ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔
ڈاکٹر صاحب کی خوبیوں، صفات وکمالات کو اگر مختصر الفاظ میں پیش کرنے کے لیے کہا جائے توکچھ اس طرح نقشہ کھینچا جا سکتا ہے:
زمانہ کو قرآن وسنت کی بنیاد پر پرکھنا اور دوسروں کو پرکھنے کے لیے استدلال کی عمارت فراہم کرنا، جدید تعلیم کے سحر میں مبتلا افراد کا اسلامی علوم پر اعتماد بحال کرنا، قرآن وسنت اور اس سے ماخوذ علوم پر اعتراضات کا شافی وکافی جواب دینا، اسلامی علوم کی، دنیا کے دیگر علوم پر برتری ثابت کرنے کے لیے علوم کے تقابلی مطالعہ کے حوالے سے گفتگو کرنا، اپنے شاگردوں میں اسلامی روح منتقل کرنا، اسلاف کے قرآن وسنت سے ماخوذ علوم پر تبحر علمی کا حامل ہونا، جدید وقدیم اسلامی مفکروں کے فکر کی نوعیت کو سمجھنا، ان کے مثبت اور کمزور پہلوؤں پر گہری نگاہ رکھنا، قرآن وسنت، سیرت اور فقہ کے موضوعات پر بلند پایہ کتابیں سامنے لانا، اجتہادی صلاحیتوں سے کام لے کر جدید دور کے جدید مسائل میں امت کی بہتر رہنمائی کرنا، اپنے دور کے ہر طرح کے فتنوں سے آشنا ہونا اور دوسروں کو بھی ان فتنوں سے بچانے کے لیے کوشاں ہونا، قرآن، سیرت، فقہ، تصوف اور تاریخ وغیرہ کے موضوعات پر عربی، انگریزی اور اردو زبانوں میں مارکیٹ میں شائع ہونے والی کتابوں پر نگاہ رکھنا اور ان کتابوں کو زیر مطالعہ لانا، امت میں ابتدائی صدیوں میں اسلامی علوم کی تدوین پر محدثوں، مفسروں، فقیہوں اور مورخوں کے کام کا وسیع مطالعہ ومشاہدہ ہونا، جدید دور کی تمدنی اور معاشرتی خرابیوں کی اصلاحِ احوال کے لیے بہتر اور مؤثر لائحہ عمل کی نشاندہی کرنا، مغربی نظام تعلیم کی پیدا کردہ خرابیوں کا پوری طرح ادراک حاصل ہونا، جدیدیت کے مثبت پہلوؤں کو اختیار کرنے اور منفی پہلوؤں کو مسترد کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہونا، مسلم معاشروں کے بالائی طبقات کی ذ ہنی الجھنوں کو سمجھنا اور ان کی ذ ہنی سطح کے مطابق ان سے بات کرنے کی استعداد کا حامل ہونا، امت کے چوٹی کے چند بڑے اسکالروں میں ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کی راہ اختیار کرنا اور امت کو اپنی نئی فکر اور نئی جماعتیں ودائراتی خول سے داغدار اور منتشر نہ ہونے دینا، ساری زندگی خاموشی سے صحیح اسلامی فکر کی ترویج میں صرف کرنا، تشہیر، شہرت، امیج، اخبارات میں اپنی تصاویر وتقاریر کی اشاعت سے بے نیاز ہونا اور بڑے علمی کاموں اور بڑی دینی خدمات کے باوجود اپنے آپ کو حقیر وفقیر سمجھنا وغیرہ۔
یہ ہے، وہ تعارفی خاکہ ہے جو ہمارے مرحوم دوست ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا ہے۔ اس خاکہ میں مزید صفات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ غازی صاحب کو قریب سے جاننے والے افراد ہمارے اس تعارفی خاکہ سے یقیناًاتفاق کریں گے۔ اس خاکہ میں شامل بہت ساری باتیں تو وہ ہیں، جن کا مشاہدہ ان کی کتابوں کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ بالخصوص درجہ ذیل کتابوں کے مطالعہ سے:
(۱) محاضرات قرآن (۲) محاضرات حدیث (۳) محاضرات فقہ (۴) محاضرات سیرت (۵) معاضرات معیشت وتجارت (۶) قرآن مجید۔ ایک تعارف (۷) مسلمانوں کا دینی وعصری نظام تعلیم۔ (۸) اسلامی بنکاری۔ ایک تعارف (۹) اسلام اور مغرب تعلقات (۱۰) خطبات بہاولپور حصہ دوم۔
موصوف کی اردو، انگریزی اور عربی میں کافی کتابیں موجود ہیں، لیکن مذکورہ کتابوں کے مطالعہ سے ان کے تبحر علمی کا بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
محترم غازی صاحب سے ہمارے تعلقات کا آغاز ان کے دعوۃ اکیڈمی کے سربراہ بننے کے وقت سے ہوا۔ یہ غالباً ۱۹۹۰ء کی بات ہے۔ اس وقت تک اردو میں ہماری متعدد کتابیں سامنے آچکی تھی۔ ملک کے دوسرے فضلا کی طرح غازی صاحب کی خدمت میں بھی ہماری کتابیں جاتی رہیں۔ غازی صاحب نے ہماری کتابوں کو اپنی دل کی آواز سمجھا اور متعد بار اس کا اظہار کیا۔ دعوۃ اکیڈمی کا سربراہ بننے کے ساتھ ہی انہوں نے سندھی زبان میں دعوتی اور علمی کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ بنایا۔ چونکہ وہ فکر کی وسیع دنیا کا مطالعہ کر چکے تھے، اس لیے سندھ کی نظریاتی کشمکش کی صورتحال میں جدیدیت سے فکری مرعوبیت میں کمی اور علمی طور پر اسلام کی صداقت کے لیے جس قسم کے لٹریچر کی ضرورت تھی، انہوں نے ہماری مشاورت سے وہ لٹریچر سندھی زبان میں منتقل کرکے، ترجمہ کروا کر شائع کرنے کی کاوش کی۔ اس سلسلہ میں مولانا امیر الدین مہر صاحب جو دعوۃ اکیڈمی کے سندھی شعبہ کے سربراہ تھے، ان کو جملہ سہولتیں فراہم کیں، چنانچہ چند سالوں کے اندر اندر دعوۃ اکیڈمی کی طرف سے اسلام کے ہر موضوع پر ضخیم اور مؤثر کتابیں شائع ہوکر سندھ کے علمی حلقوں میں اعزازی طورپر تقسیم ہوئیں۔ غازی صاحب نے اس سلسلہ میں جس دردمندی، فکرمندی اور کاوش کا مظاہرہ کیا اور اس کام میں درپیش انتظامی رکاوٹوں کو دور کیا، وہ ان کی دعوتی کاموں سے بے پناہ لگن کا ثبوت ہے۔
اگرچہ علمی اعتبار سے اس وقت بھی غازی صاحب کا مطالعہ کافی تھا، دینی مدرسہ کے فضلا سے بہرہ وری کی وجہ سے قرآن وسنت اور فقہی مسائل میں وہ اس وقت بھی غیرمعمولی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطالعہ اور فکر میں وسعت ہوتی چلی گئی اور اس مطالعہ میں ہر پہلو سے اضافہ ہونے لگا۔ دعوۃ اکیڈمی کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں دنیا بھر کے علمی اداروں اور یونیورسٹیوں کی طرف سے مجالس مذاکرات اور سیمیناروں میں شرکت کے مواقع ملتے رہے۔ عربی اور انگریزی میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت اور مطالعہ کے شغف نے ان کی فکری صلاحیتوں کو غیرمعمولی نشوونما دی۔ ان کی تقاریر جو اسلام کے ہر اہم موضوع پر ہوتیں، ان تقاریر میں وہ سامعین کو اتنی معلومات فراہم کرتے تھے کہ وہ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ معلومات کے ساتھ ساتھ وہ ان کے اندر حرارت وگرمی بھی منتقل کردیتے تھے۔ تقاریر پر مشتمل ان کی بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ان کی اس غیرمعمولی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔
غازی صاحب نے آج سے غالباً اٹھارہ سال پہلے اس عاجز کو جدید اسلامی مفکروں کے فکر کے تجزیاتی مطالعہ پر لکھنے کے لیے کہا تھا۔ (ان کے کسی خط میں بھی اس کا ذکر موجود ہے) الحمدﷲ ان کے اکسانے پر راقم السطور نے اس موضوع پر تین چار کتابیں لکھیں، اگرچہ یہ کتابیں دعوۃ اکیڈمی کی طرف سے شائع نہ ہوئیں، ہمارے ہی ادارہ کی طرف سے شائع ہوئی ہیں۔
غازی صاحب سے اس عاجز کی آخری ملاقات ستمبر۲۰۰۶ میں (جب وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے) ہوئی۔ راقم دعوۃ اکیڈمی ہی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ برسوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کی صحت دیکھ کر مجھے سخت تشویش ہوئی۔ راقم نے انہیں اس طرف توجہ دلائی۔ کہنے لگے، شوگر کی تکلیف ہوگئی ہے اور کچھ یونیورسٹی کے مسائل کا دباؤ بھی ہے۔ مزید کہنے لگے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ گہرا اسلامی ذہن رکھنے والے افراد، جن سے ہمیں تعاون کی زیادہ توقعات رہی ہے، سب سے زیادہ مسائل وہی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے دعوۃ اکیڈمی کی سربراہی کے دوران اور اب صدارت کے دوران انہی افراد کا تقرر کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے بحران پیدا کرنے اور تلخیوں کے ماحول کو فروغ دینے میں یہی افراد سب سے زیادہ پیش پیش ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے دعوۃ اکیڈمی کی سربراہی کے دور میں سوویت یونین سے آزاد مسلم ریاستوں کے لیے ایک سو سے زائد کتابوں کے تراجم شائع کرکے وہاں پھیلائے تھے۔ اب جب دوبارہ ان کتابوں کی اشاعت کا فیصلہ ہوا تو ان ساری کتابوں کے بٹر غائب تھے۔ ایک گروہ چاہتا ہے کہ بس ان کی فکر ہی کی اشاعت ہوتی رہے۔ ان کے مکتبہ فکر سے باہر کے علما وفضلا کے فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے۔
اسلام آباد کے اسی دورہ کے دوران راولپنڈی کی ایک فاضل شخصیت جو علمی اعتبار سے ممتاز حیثیت کی حامل ہے، اس نے راقم الحروف سے کہا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اور ان کے بھائی محمد غزالی صاحب نے حکومت وقت سے تعاون کرنے میں اہم کردار ادا کرکے، علماے حق کی حکومت وحکمرانوں سے بے نیازی والی روایت کو سخت زک پہنچائی ہے۔ راقم نے اپنے خط میں ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا جو خطوط میں شامل ہے ۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ نقطہ نگاہ کافی وزنی ہے کہ انہوں نے حکومت وحکمرانوں سے مالی فائدہ یا مراعات حاصل نہیں کی،بلکہ اپنی بساط کے مطابق اصلاح احوال اور بہتری کی کوشش کی، البتہ مشرف حکومت میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے ان کی شرکت کا فیصلہ ایسا تھا جس پر ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی دکھ ہوا۔ غازی صاحب کو توقع تھی کہ حکومت سے وابستگی سے وہ زیادہ بہتر طور پر خدمت سرانجام دے سکیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، چنانچہ جوں ہی انہیں اس کا احساس ہوا کہ حکومت وقت انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کررہی ہے تو انہوں نے بغیر تامل کے استعفیٰ دے دیا۔
غازی صاحب اپنی ذات میں انجمن تھے۔ اپنی تقاریر، گفتگو، اور کتابوں کے ذریعہ اُس طبقہ تک اسلام کی دعوت پہنچاتے تھے جس طبقہ تک علما کی رسائی دشوار تھی۔ فرد چلے جاتے ہیں۔ ان کی باتیں اور ان کا کام باقی رہ جاتا ہے، باتوں اور کام کو بھی اخلاص اور سوزِ دروں ہی بقا اور استحکام بخشتا ہے۔ غازی صاحب میں اخلاص اور سوز دروں کے اجزا غالب صورت میں موجود تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزش معاف فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ (آمین)
ہم نے اپنی کتاب ’’عصر حاضر کی شخصیات میری نظر میں‘‘ میں غازی صاحب کا تعارفی خاکہ لکھا ہے۔ اس کتاب میں ان کے خطوط بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب ان کی زندگی میں ہی چھپی ہے اور ان کی نظر سے گزر چکی تھی۔ یہ تعارفی خاکہ اور خطوط یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔
(۲)
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ملک وملت کا بڑا سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن صلاحیتوں، خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے، انہیں دیکھ کر ملک وقوم کے بارے میں یہ حوصلہ بڑھتا ہے کہ جس قوم وملک میں اس طرح کی شخصیتیں موجود ہوں، ان شاء اﷲ وہ قوم سرسبز وآباد ہوگی اور اسے نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ وہ انگریزی، عربی اور اردو زبان میں یکساں صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں ان زبانوں میں تحریر وتقریر کا یکساں ملکہ حاصل ہے۔ فرانسیسی زبان بھی جانتے ہیں۔ دینی مدرسے میں فارسی بھی پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیرمعمولی ذہانت سے نوازا ہے۔ پاکستان میں عالم اسلام کے جدید وقدیم اسلامی مفکروں اور فاضلوں کے لٹریچر پر جتنی عمیق نظر ان کی ہے، اتنی گہری نظر بمشکل چند افراد کی ہوگی۔ ملت اسلامیہ کو دور جدید میں درپیش چیلنج، علمی، نظری اور عملی طور پر اس چیلنج کی نوعیت اور اس سے عہدہ بر آہونے کے لیے نظریاتی وعملی خاکہ اور اس کے لیے فکر مندی اور اضطراب، ان سارے معاملات میں ملک میں ڈاکٹر موصوف جیسی شخصیتیں خال ہی نظر آتی ہیں۔
مختلف موضوعات پر ان کی تقاریر سننے اور مضامین پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف نے متعلقہ موضوع پر پڑھنے والے کے سامنے مواد کے اتنے سارے پہلو رکھ دیے ہیں کہ ان کے لیے متعلقہ موضوع کی گہرائی کو سمجھنا آسان ہوگیا ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے دعوہ اکیڈمی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے دعوتی نقطہ نگاہ سے اردو، سندھی اور مختلف زبانوں میں جو لٹریچر منتخب کرکے شائع کرنے کا انتظام کیا، اسے دیکھ کر دل بے ساختہ ان کے حسن انتخاب پر داد دینے لگتا ہے۔ دعوہ اکیڈمی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے اسلامی دعوت کے فروغ کے لیے اسلامی دنیا اور غیر اسلامی دنیا کے طویل دورے کیے، ہر جگہ اہل علم اور اہل فکر سے نشستیں کیں، ان سے حالات سنے اور ان کے سامنے اپناحال دل پیش کیا۔ ان طویل دعوتی دوروں میں جہاں انہوں نے مختلف ممالک میں دعوتی کام کے پھیلاؤ کے لیے تدابیر کیں اور عملی راہیں نکالیں، وہاں ان دوروں سے عالم اسلام کے حالات کے سلسلے میں انہیں بے پناہ تجربہ ومشاہدہ بھی ہوا۔ ہماری سندھی زبان، جو جدید اسلوب میں دعوتی لٹریچر سے خالی تھی، اس میں انہوں نے بعض ایسی اہم بنیادی کتابیں شائع کرکے پھیلا دیں جن کتابوں کی اشاعت سندھ نیشنل اکیڈمی جیسے کمزور اداروں کے لیے مشکل تھی۔ اس طرح انہوں نے سندھی نوجوانوں اور سندھ کے علم وادب پر احسان فرمایا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم بھی عطا فرمایا ہے، وہ علم وفضل کے حامل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب ممتاز عالم دین تھے۔ جن کے برصغیر ہند کے ممتاز علما وصلحا سے گہرے تعلقات تھے۔ ان کے گھر پر علما وصلحا کی آمد ورفت رہتی تھی۔ وہ کتابوں کے ماحول میں پلے اور بڑھے۔ ان کی ابتدائی تربیت نہایت پختہ تھی۔ انہیں شروع سے فکری طور پر صحیح فکری خطوط اور لائن حاصل ہوگئی، چنانچہ ذہانت، صحیح تربیت، فطرت سلیمہ کی بڑی حد تک حفاظت اور صحیح اساتذہ کی رہنمائی اور مسلسل مطالعے ومشاہدے نے ان کو علم وعمل کی ایک مثالی اور پاکیزہ شخصیت بنا دیا۔ ڈاکٹر موصوف کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دل بھی عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی راہیں کھول دی ہیں۔ تقریر سے بھی، تو تحریر سے بھی اور حکومتی اداروں کے ذریعہ سے بھی۔ اب سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بنچ کے جج کی حیثیت سے اس خدمت کی توفیق دی ہے۔
ان کی ان ساری سعادتوں میں جہاں ان کے گہرے مطالعے ومشاہدے اور طویل تجربات کو عمل دخل حاصل ہے، وہاں اس میں ان کی ایک خاص صفت کو بھی بنیادی عمل دخل ہے۔ وہ صفت ان کی بڑے پن سے دستبرداری، چھوٹے پن کا مظاہرہ اور عاجزی وخاکساری کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باصلاحیت افراد پر ساری نوازشیں ان کی اس خاص ادا کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں جس کا اندازہ ظاہر بین افراد کے لیے مشکل ہے۔ اس عاجز کے ساتھ ان کی محبت محض ان کے حسن ظن کی بنا پر ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی خدمت کا وسیع ترکام لے اور اخلاص عظمیٰ کی دولت عطا فرمائے۔ (آمین)
(بشکریہ ماہنامہ بیداری، حیدر آباد)
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ : ایک اسم با مسمٰی
جسٹس سید افضل حیدر
(۲۷ ستمبر ۲۰۱۰ء کو وفاقی شرعی عدالت میں ایک تعزیتی ریفرنس میں گفتگو۔)
عزت مآب جسٹس آغا رفیق احمد خان، (چیف جسٹس، وفاقی شرعی عدالت)
عزت مآب جسٹس شہزادو شیخ، (جج، وفاقی شرعی عدالت)
عزت مآب جسٹس (ر) فدا محمد خان، (عالم رکن شریعت اپیلٹ بنچ سپریم کورٹ)
عزت مآب جسٹس محمد الغزالی، (عالم رکن، شریعت اپیلٹ بنچ سپریم کورٹ)
السلام وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
جسٹس ڈاکٹر محمود احمد غازی کل صبح اپنے خالق حقیقی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے راہئ ملک عدم ہوئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ آج اِس مجلس ترحیم میں ہم مرحوم کے ذکر خیر اور دعائے مغفرت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔
۱۸؍ ستمبر ۱۹۵۰ء کو حافظ محمد احمد فاروقی کے ہاں دہلی میں جسٹس ڈاکٹر محمود احمد غازی پیدا ہوئے۔ آپ نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرلیا تھا۔ آپ نے لسانیات میں خاصا عبور حاصل کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۷۲ء میں ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۸۸ء میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک سٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے ملکی و بین الاقوامی سطح پر متعدد جامعات کی تشکیل میں بھرپور حصہ لیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر بھی رہے۔ دو بار اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مقرر ہوئے۔ وزارت مذہبی امور کا قلمدان بھی آپ کے سپرد رہا۔ فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب بھی رہے۔ عربی جریدہ ’’الدراسات الاسلامیہ‘‘ کے ایڈیٹر اور معروف علمی رسالہ فکرونظر (اردو) کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کئی برس کام کیا۔ آپ متعدد اداروں کے مشیر تھے اور تقریباً ۳۰ کتب کے مصنف تھے جن میں سے ۷ کتب انگریزی زبان میں، ۵ کتب عربی زبان میں اور ۱۸ کتب اردو زبان میں لکھی گئیں۔
مرحوم جسٹس غازی محمود احمد بڑے باحیا انسان تھے۔ آپ خلوص کا پیکر تھے۔ خلوص کے رشتے عمر بھر قائم رہتے ہیں۔ غازی صاحب سے میرا پہلا تعارف دو دہائیاں قبل ۱۹۹۰ء میں ہوا جب ہم دونوں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ جسٹس محمد حلیم سابق چیف جسٹس پاکستان ہمارے چیئرمین تھے۔ بہت اچھی ٹیم تھی۔ میرے ایما پر کونسل نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے قرآن و سنت کی کسوٹی پر رائج الوقت قوانین کو جانچنے کا فریضہ ایک کمیٹی کے سپرد کیا اور چیئرمین نے ہم دونوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا۔ ہم نے مل کر کام شروع کیا۔ یہ فکری و علمی رفاقت دوستی کا روپ دھار گئی۔ بفضلہ تعالیٰ رفاقت کا سفر جاری رہا اور پھر ۲۶؍ مارچ ۲۰۱۰ء سے ہم اس عدالت میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔
جناب آغا صاحب!
ہم دونوں نے دو بار اکٹھے حج بھی کیا اور اس طرح مجھے غازی صاحب کی ایمانی کیفیات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ مرحوم ایک متقی، پرہیزگار اور مخلص انسان تھے۔ اسلامی احکام کی بجاآوری آپ کا طرۂ امتیاز تھا۔ میں اس موقع پر آپ کو بتلاتا چلوں کہ غازی صاحب نے ایک بار علامہ محمد اقبالؒ اور دوسری بار قائداعظم محمد علی جناحؒ کے نام پر حجِ بدل بھی کیے تھے۔ آپ کو ان دونوں شخصیتوں سے اور ان کے فیض سے حاصل ہونے والے اس مملکت خداداد پاکستان سے بہت پیار تھا۔
غازی صاحب کی شخصیت کو ایک نشست میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ان کے مشاغل اور ان کی کامرانیوں کی فہرست خاصی طویل ہے جس کا ہر ہر جزو بذاتِ خود ایک دفتر ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسی ہستیاں دیکھی ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دل و دماغ، علم و عمل اور عمیق بصیرت جیسی صلاحیتوں سے سرفراز کیا ہو۔ آپ کی نگاہ بلند تھی اور آنے والے حالات کا جائزہ لینے اور اس کے لیے تیار رہنے کی صلاحیت بھی غازی صاحب میں موجود تھی۔ بلاشبہ آپ اسم بامسمیٰ تھے۔ تحقیق ان کا وظیفہ تھا۔ مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ اِن سے ہم کلام ہونے والا یہ سمجھتا کہ وہ ایک متحرک لائبریری اور زندہ کمپیوٹر سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ جو بات کہتے، اس کے پیچھے دلیل ہوتی اور حوالہ بھی فوری طور پر دے دیتے۔ ان کی ذاتی لائبریری اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ موصوف تحقیق‘ کھوج اور دریافت میں کتنے کوشاں رہتے۔
غازی صاحب قومی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں اپنا مافی الضمیر بیان کرنے پر قادر تھے۔ اردو کے علاوہ کبھی کبھی فارسی میں اشعار بھی کہہ لیتے۔ قرآنی علوم، سنت مطہرہ، سیرت، فقہ اور قانون کے علاوہ ادب سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کی بنیادی دلچسپی اسلام اور دین کے مختلف شعبے تھے۔ خطبات بہاولپور (۲) کے عنوان سے اسلام کے بین الاقوامی تعلقات پر آپ کے بارہ خطبات ایک قابل قدر کارنامہ تھا۔ آپ کے متعدد خطبات اسلامی فقہ میں ایک ممتاز مقام حاصل کرچکے ہیں۔
جناب آغا صاحب!
ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر ایک معلم تھے۔ آپ نے اس میدان میں بھی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے اہم کردار ادا کیا۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ نے کئی جامعات کی تشکیل میں بھرپور حصہ لیا۔ عملی زندگی کا ایک طویل حصہ آپ نے درس و تدریس میں گزارا۔ سینکڑوں طالب علموں نے آپ سے رہنمائی حاصل کی۔
غازی صاحب نہ خود زندگی میں کبھی مایوس ہوئے، نہ کسی کو انہوں نے مایوس کیا۔ غازی صاحب سے مشورہ طلب کرنے والا یا مدد مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ آپ نے طالب علموں کے ساتھ مشفقانہ رویہ روا رکھا۔ میری نظر میں جسٹس غازی ایک درویش فقیہ اور عالم باعمل تھے۔
غازی صاحب نے اصولوں پر کبھی مفاہمت نہ کی۔ آپ نے ہمیشہ اعلیٰ اسلامی اقدار کی پاسداری کی اور نتائج کی پروا کیے بغیر صحیح بات سے انحراف نہ کیا۔ توکل اور قناعت آپ کا اثاثہ تھا، لہٰذا آپ کے پاؤں کبھی نہ ڈگمگائے۔
غازی صاحب کی زندگی کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اسلامی اخلاق کی پابندی اور احکام اسلام کی مخلصانہ پیروی اس تیزرفتار زمانے میں بھی ممکن ہے۔ بقول اقبالؔ آپ شجر سے پیوستہ رہتے ہوئے بہار کی امید کے داعی تھے۔
غازی صاحب اپنی مجالس و محافل کو اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے مزین کرتے تھے۔ آپ نہایت منکسر المزاج اور حلیم الطبع شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل ہوئے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی کامرانیوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹا اور اپنے علم سے کبھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی سوچ بھی ان کے پاس سے نہیں گزری۔ آپ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سن کر آب دیدہ ہو جاتے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بزرگوں کا احترام آپ کا وطیرہ تھا۔
غازی صاحب مرحوم کو وطن عزیز کے ساتھ بہت پیار تھا۔ پاکستان کے استحکام کے لیے اکثر دعائیں کرتے۔ آپ کی انہی صفات کے پیش نظر ہمارے محترم چیف جسٹس آغا رفیق احمد خان نے وفاقی شرعی عدالت کے لیے غازی صاحب کا نام خصوصی طور پر تجویز کیا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ علم کے اس منبع سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، لیکن کسے معلوم کہ دوسری جانب یہی سورج اپنی آب و تاب سے طلوع ہوچکا ہے۔
بلھےؔ شاہ اساں مرناں ناہیں
گوراں وچ پئے ہور
ایک باکمال شخصیت
پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی
ڈاکٹر محمود احمد غازی کے ساتھ میری پہلی ملاقات مئی ۱۹۸۳ ء میں ہوئی۔ ان دنوں کراچی جاتے ہوئے تین چار دن کے لیے اسلام آباد میں قیام کا موقع ملا۔ میری خواہش تھی کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی جا کر ایل ایل ایم (شریعہ) کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جائیں۔ اس پروگرام کے بارے میں دینی جامعات کے طلبہ کے ہاں تذکرہ رہتا تھا اور مجھے ذاتی طور پر کئی اساتذہ نے اس میں داخلہ لینے کی ترغیب دی تھی۔ میں اپنے ایک عزیز کے ہمراہ جب فیصل مسجد پہنچا تو مین گیٹ کے سامنے استقبالیہ پر ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جس کا تعلق اسلام آباد میں واقع ایک دینی مدرسے سے تھا۔ وہ دن کے وقت ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی میں ملازمت کرتا تھا اور چھٹی کے بعد دینی مدرسہ کی خدمت کرتا تھا۔ اُس نے پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنی اور کہنے لگا:
’’میں آپ کی ملاقات ایسے اساتذہ سے کرا دیتا ہوں جو ایل ایل ایم (شریعہ) کے طلبہ کو پڑھاتے ہیں اور اس پروگرام کے بارے میں خوب جانتے ہیں، آپ اُن سے مشورہ کر لیں۔‘‘
یہ کہہ کر وہ مجھے ڈاکٹر احمد حسن کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر احمد حسن صاحب کی ٹیبل کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں اُن کے سامنے بیٹھ گیا ، اپنا تعارف کرایا اور جب انہیں یہ بتایا کہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا مبلغ ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی پذیرائی فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب سے اجازت لینے کے بعد ہم باہر نکلے اور بائیں طرف آگے بڑھے تو ایک کمرے کے باہر ’’محمود احمد غازی‘‘ کے نام کی تختی لٹک رہی تھی۔ میرے ساتھی نے کہا، یہ صاحب آپ کو بہت اچھا مشورہ دیں گے، آپ ان سے تفصیل کے ساتھ بات کریں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئے۔ غازی صاحب کی ٹیبل پر مسودات کے ڈھیرتھے۔ پوچھنے لگے : آپ کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ میں نے اپنا مدعا بتایا۔ میں نے کہا کہ:
’’ میرا تعلق نیو ٹاؤن سے ہے اور میں ہفت روزہ ’’ختم نبوت‘‘ کا منیجنگ ایڈیٹر ہوں‘‘۔
کہنے لگے :
’’ میں بہت اہتمام کے ساتھ ہفت روزہ ’’ختم نبوت‘‘ پڑھتا ہوں۔ آپ کے اداریے، مضامین اور نظمیں بھی پڑھتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے براہِ راست ملاقات ہوئی‘‘۔
میں نے عرض کیا:
’’ایل ایل ایم (شریعہ) میں داخلہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟‘‘
کہنے لگے :
’’آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اشتہار آئے تو درخواست دے دیں۔ داخلہ ہو جائے گا۔‘‘
۱۹۸۳ء کے اواخر میں مجھے کراچی سے شفٹ ہو کر اسلام آباد آنا ہوا۔ اُس سال وفاق المدارس نے سولہ سالہ نصاب مرتب کر کے دینی جامعات کے مہتمم حضرات کو ہدایت کی تھی کہ اس کے مطابق اپنے اپنے مدارس میں پڑھائی کا انتظام کریں۔ اس نصاب پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے مولانا عبد الحکیم رحمہ اللہ نے جامعہ فرقانیہ راولپنڈی میں اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے دینی مدارس کے تمام مہمتمین اور سینئر اساتذہ نے شرکت کی جن میں حاجی اختر حسن (مرحوم) بانئ و مہتمم جامعہ فریدیہ اسلام آباد بہت نمایاں تھے۔ مولانا عبد الحکیم رحمہ اللہ اور قاری سعید الرحمن انہیں بہت پروٹوکول دے رہے تھے۔ میں نے حاجی صاحب سے ملاقات کی تو مولانا عبد الحکیم نے ازراہِ شفقت حاجی صاحب کے سامنے میری تعریف کی اور فرمایا کہ چشتی صاحب فاضل وفاق بھی ہیں اور لاء گریجویٹ بھی ہیں۔ حسنِ اتفاق سے حاجی صاحب کو جامعہ فریدیہ میں صدر مدرس کی پوزیشن کے لیے ایک ایسے استاذ کی تلاش تھی جس کا تعلق علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ سے بھی ہو۔ اس ضمن میں میرا تذکرہ مولانا ظہور احمد علوی صاحب بھی حاجی صاحب سے کر چکے تھے۔ حاجی صاحب نے اس بارے میں سیٹھ ہارون جعفر صاحب (مرحوم) سرپرست جامعہ فریدیہ سے کہا۔ سیٹھ صاحب مجھے پیر طفیل احمد فاروقی رحمہ اللہ کی وجہ سے جانتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مئی ۱۹۸۴ء میں، میں نے جامعہ فریدیہ میں اپنے فرائض سنبھالے۔
جامعہ فریدیہ چونکہ فیصل مسجد کے قریب واقع ہے، اس لیے فیصل مسجد آنے جانے کے مواقع بڑی سہولت کے ساتھ میسر آئے۔ جامعہ فریدیہ میں قیام کے دوران میں جب بھی ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی کی لائبریری میں جاتا تھا تو اکثر و بیشتر غازی صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک سال جامعہ فریدیہ کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد جون ۱۹۸۵ء میں مجھے دعوۃ اکیڈمی میں بطور لیکچرر کام کرنے کا موقع ملا۔ دعوۃ اکیڈمی جس کا اساسی نام اکیڈمی برائے تربیت ائمہ (Academy for training of Imams) تھا اور بنیادی طور پر ائمہ مساجد اور خطبا و اساتذہ کی تربیت کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اس میں تربیت ائمہ کا پہلا پروگرام ۱۹۸۵ء کے اواخر میں شروع ہوا۔ اس پروگرام کی تخطیط میں غازی صاحب نے بھرپور حصہ لیا اور جب ہم نے کورسز کی تقسیم کی تو غازی صاحب نے اسلام کے سیاسی نظام کے موضوع پر لیکچرز دینے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ شروع شروع میں غازی صاحب ہفتہ میں صرف ایک لیکچر کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن پھر ان کی دلچسپی بڑھی اور انہوں نے ہفتہ میں دو لیکچرز لے لیے۔ یہ وہ دَور ہے جس میں غازی صاحب کے ساتھ ہماری بہت frankness پیدا ہو گئی۔ میں ان دنوں صبح کے وقت لال کڑتی چوک سے بہت سپیشل پان بنوا کر لاتا تھا۔ غازی صاحب لیکچر سے فارغ ہو کر آتے تھے تو ہم چائے پیتے تھے، پان کھاتے تھے اور بہت کھل کر گفتگو ہوتی تھی۔ دعوۃ اکیڈمی کے رفقا سب جمع ہوتے تھے اور بلا تکلف بات چیت ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بعض مرتبہ موسم سرما میں پرنس بیکرز کراچی کمپنی کے سامنے کرسیاں لگا کر ہم بیٹھتے تھے اور بہت light mood میں غازی صاحب کے ساتھ سلسلۂ کلام چلتا رہتا تھا۔ غازی صاحب جب تک ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی میں رہے ، آپ کا مزاج خالص علمی رہا۔ علمی گفتگو کرتے ہوئے آپ کو وقت کی فکر نہیں رہتی تھی۔ گھنٹہ کے بجائے ڈیڑھ اور کبھی دو گھنٹے شرکاے کورس کے ساتھ سوال و جواب میں گذار دیتے تھے۔
۱۹۸۸ ء کے وسط میں دعوۃ اکیڈمی کے انتظامی معاملات نشیب و فراز کا شکار ہوئے اور بعض ایسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے اکیڈمی کے تقریباً تمام رفقا بری طرح متأثر ہوئے ۔ ان حالات کے نتیجہ میں یونیورسٹی کی اعلیٰ انتظامیہ نے محمود احمد غازی کو دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل کے منصب کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ منظر اب تک میری نظروں کے سامنے ہے جب غازی صاحب اپنا منصب سنبھالنے کے لیے کراچی کمپنی میں واقع دعوۃ اکیڈمی کے دفتر میں تشریف لائے۔ ہم نے مین گیٹ سے باہر آ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آڈیٹوریم ان کے ساتھ گئے۔ اس موقع پر آپ نے دعوۃ اکیڈمی کے رفقا کے سامنے بہت مختصر سا خطاب کیا ۔ پھر ہمیں اپنے ساتھ مدیر عام کے دفتر میں لے آئے اور اکیڈمی کے مختلف شعبوں کے بارے میں تبادلۂ خیال کیا۔
ڈاکٹر غازی صاحب کی قیادت میں دعوۃ اکیڈمی نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ قسم قسم کے تربیتی پروگرام شروع ہوئے۔ آرمی آفیسرز کے لیے تربیتی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اساتذہ اور اُدبا کے لیے ورکشاپ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بچوں کے ادب کا شعبہ قائم ہوا۔ خط و کتابت کورسز کے ضمن میں مطالعہ تفسیر، مطالعہ حدیث اور مطالعہ اسلام کے عنوان سے پروگراموں کا آغاز ہوا۔ ان کورسز کی سالانہ enrollment پینتالیس پچاس ہزار کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ ان بہت سارے پروگراموں کے علاوہ دوپروگرام ایسے شروع ہوئے جو میری براہِ راست دلچسپی کے تھے جن کی تحریک میں نے پیش کی اور غازی صاحب نے انہیں سراہتے ہوئے مجھے ان کی تخطیط کی ہدایت کی۔ ایک بین الاقوامی تربیت ائمہ کورس جس میں زیادہ تر وسط ایشیا کی ریاستوں کے ائمہ مساجد اور خطبا شریک ہوتے رہے۔ بعد میں اس کا دائرہ پھیلا اور کئی ممالک مثلاً سری لنکا، فجی، نیپال، تھائی لینڈ، سنکیانگ اور برما کے ائمہ بھی اس پروگرام سے مستفید ہوتے رہے۔ یہ دعوۃ اکیڈمی کا ایک منفرد پروگرام تھا جس میں غازی صاحب بہت دلچسپی لیتے تھے۔ ڈاکٹر حسین حامد حسان، ڈاکٹر احمد العسّال (مرحوم) اور ڈاکٹر طیب زین العابدین جیسے اساتذہ اس کورس کے شرکا کو لیکچر دینے کے لیے آتے تھے اور بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ دوسرا کورس مطالعۂ قادیانیت کے عنوان سے ان ائمہ اور خطبا کے لیے ترتیب دیا گیا جنہوں نے دعوۃ اکیڈمی سے تربیت ائمہ کا عمومی کورس کر لیا ہو۔ قادیانیت کے موضوع پر چونکہ غازی صاحب نے بھرپور مطالعہ کیا ہوا تھا اور آپ اس موضوع کی اہمیت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے اس پروگرام میں بھی بہت دلچسپی لی۔ غازی صاحب نے مجھے ایک بار نہیں، کئی بار اس بات کی ترغیب دی کہ ’’ قادیانیت کا علمی محاسبہ‘‘ کی تعریب کا اہتمام کیا جائے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ :
’’ جوشخص اس کتاب کو عربی زبان کے قالب میں ڈھال لے گا، میں اُس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مقصد یہ کہ ایسے شخص کے جنتی ہونے میں کم از کم مجھے کوئی شک نہیں ہے۔‘‘
مطالعۂ قادیانیت کے اس کورس کو بڑی پذیرائی ملی اور یہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، لیکن ۱۹۹۹ء میں جب میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جائن کی تو یہ پروگرام بند ہو گیا۔ بین الاقوامی تربیت ائمہ کا کورس بھی بعد میں بحران کا شکار ہو گیا۔ دعوۃ اکیڈمی میں ڈاکٹر غازی صاحب بطور ڈائریکٹر جنرل ۱۹۸۸ء میں آئے تھے اور ۱۹۹۴ء تک اس منصب پر فائز رہے۔ اس سات سال کے عرصہ میں ہمیں براہِ راست ان کی قیادت میں کام کرنے کا موقع ملا اور ان سے بھرپور استفادہ کے مواقع میسر آتے رہے۔ عام طور سے جامعات کے اساتذہ کا اختصاص کسی ایک مجال (field) میں ہوتا ہے اور وہ اُسی مجال میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن غاز ی صاحب کا معاملہ اس اعتبار سے بالکل مختلف تھا۔ آپ تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، کلام، ادب اور تاریخ کے ادق موضوعات پر فی البدیہ گفتگو کرتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے آپ نے اس موضوع پر بولنے کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ تیاری کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قوی حافظہ دیا تھا کہ اس کا تصور معاصر علما میں نہیں کیا جا سکتا۔
نومبر ۲۰۰۵ء کی بات ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبۂ اقبالیات اور کلیہ علوم اسلامیہ نے علامہ اقبال کے یوم ولادت کی مناسبت سے ایک سیمینار منعقد کیا۔ اس سیمینار میں مختلف جامعات کے معروف و مشہور اقبال شناس جمع تھے۔ ڈاکٹر غازی صاحب نے علامہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو شروع کی۔ مسلسل دو گھنٹے آپ بولتے رہے۔ رقت اور جذبات کی ایسی فضا قائم ہوئی کہ حاضرین کے رخساروں پر بلااختیار آنسو بہتے رہے۔ ڈاکٹر الطاف حسین (وائس چانسلر ) جو سیمینار کی صدارت کر رہے تھے، جب صدارتی خطبہ کے لیے اُٹھے تو صدارتی کلمات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکے۔ اُس دن غازی صاحب خود بھی اپنے قابو میں نہیں تھے۔ آپ کا ایک ایک لفظ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہا تھا اور سامعین کے دل و دماغ کو گرما رہا تھا۔
عام طور پر ہمارے ہاں جو اساتذہ تقریر کے ماہر ہوتے ہیں، ان کی تحریر اچھی نہیں ہوتی اور جن کی تحریر اچھی ہوتی ہے، وہ تقریر میں کمزور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر غازی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہ یک وقت جہاں تحریر کا بہت قوی ملکہ عطا فرمایا تھا، وہاں تقریر کی بہت عمدہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ آپ اُردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں پوری مہارت کے ساتھ بول بھی سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے۔ ایک ہی نشست میں جب عربی بولتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ آپ عربی زبان کے ماہر ہیں اور جب انگریزی بولتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ آپ انگریزی کے استاد ہیں۔ اُردو تو خیر آپ کی مادری زبان تھی۔ فارسی بہت شستہ بولتے تھے اور فرنچ کے ساتھ بھی بہت حد تک مناسبت رکھتے تھے۔
۲۰۰۱ء میں جب غازی صاحب وفاقی وزیر مذہبی اُمور کے منصب پر فائز تھے تو تعلیم الاسلام کالج کراچی کی انتظامیہ نے اپنی پچاس سالہ تقریبات کا اہتمام کیا۔ تعلیم الاسلام کے موجودہ ریذیڈنٹ ڈائریکٹر جناب عبد الباقی فاروقی صاحب میرے پاس آئے اور ڈاکٹر غازی صاحب کوافتتاحی تقریب میں مہمانِ خصوصی کے طور پر دعوت دینے کا عندیہ ظاہر کیا۔ وہ فکر مند تھے کہ غازی صاحب اپنی مصروفیات سے وقت نکال سکیں گے یا نہیں اور کراچی جانے پر آمادہ ہوں گے یا نہیں۔ بہرحال ہم دونوں غازی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں تعلیم الاسلام کالج کی خدمات پر بریفنگ دی اور تقریبات میں شرکت کی دعوت دی۔ غازی صاحب کہنے لگے :
’’ میں تعلیم الاسلام کے بانی پیر طفیل احمد فاروقی رحمہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں۔ وہ اس دَور کے کبار اصحاب بصیرت میں سے تھے۔ میں ان شاء اللہ ضرور حاضر ہوں گا۔‘‘
پھر اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ہمیں تاریخ دے دی۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ڈاکٹر غازی صاحب نے انتہائی مؤثر انداز میں خطاب کیا۔ کراچی کے تمام دینی جامعات کے مہتممین اور اساتذہ کا جم غفیر تھا۔ غازی صاحب نے فرداً فرداً سب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آپ نے اس منصوبہ کا اظہار بھی کیا جو دینی مدارس اور جامعات کے ضمن میں آپ کے ذہن میں تھا۔
کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو آغاز سے ڈاکٹر غازی صاحب کی سرپرستی حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کے نوتعمیر کردہ بلاک (شاہ ولی اللہ بلاک) کے افتتاح کا مرحلہ آیا تو آپ کو بلایا گیا۔ غازی صاحب نے بلاک کا افتتاح کیا اور تقریب سے خطاب کیا۔ ۲۰۰۰ء سے لے کر اب تک مجھے یاد نہیں کہ ہم نے آپ کو اپنے کسی پروگرام، ورکشاپ، سیمینار، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے زبانی امتحان کے لیے بلایا ہواور آپ نے انکار کیا ہو۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کے بہت سے اسکالرز نے آپ کی نگرانی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات مرتب کیے۔ طلبہ کے ساتھ آپ کا رویہ غیر معمولی، نرم اور ہمدردانہ ہوتا تھا اور ہمیں بعض مرتبہ اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ غازی صاحب اس حد تک نرم رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے سے کوئی عالم یا علامہ نہیں بنتا، بس اتنا ہو جاتا ہے کہ پڑھنے لکھنے سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس سطح کے طلبہ کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ پڑھنے اور لکھنے کی طرف آئیں تا کہ ان میں قلم کے استعمال کا ملکہ پیدا ہو۔
اپریل ۲۰۱۰ء میں ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کے اسکالرز کی ورکشاپ ہو رہی تھی۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ طلبہ اپنے اپنے موضوع کا تعین کریں اور خاکہ ہاے تحقیق تیار کر لیں تا کہ انہیں بورڈ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ڈاکٹر غازی صاحب کو اس ورکشاپ میں لیکچرز دینے کے لیے دعوت دی گئی۔ آپ کا لیکچر چار بجے رکھا گیا تھا، لیکن آپ اڑھائی بجے تشریف لے آئے۔ میرے آفس میں بیٹھ گئے اور خوب گپ شپ لگاتے رہے۔ دوسرے دن آپ کا لیکچر مغرب کے بعد تھا، لیکن آپ عصر کے وقت تشریف لے آئے اور عشا تک ہمارے ساتھ رہے۔ غازی صاحب کے رویے میں اب غیر معمولی وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ طلبہ آپ سے سوال کریں اور آپ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ جواب دینے میں اب آپ کے ہاں بخل کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا۔
ڈاکٹر غازی صاحب کے ساتھ میری ملاقات سینکڑوں نہیں، ہزاروں مرتبہ ہوئی ۔ ہم نے اُن سے بہت کچھ سیکھا۔ میرے ایم فل کے مقالہ پر آپ نے رپورٹ لکھی اور بہت خوبصورت رپورٹ لکھی۔ جس دن میرے ایم فل کا زبانی امتحان تھا، اُس دن اتفاق سے آپ کو غلام اسحاق خان (مرحوم) نے ایوانِ صدر بلا لیا۔ مجھے بہت پریشانی لاحق ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایوانِ صدر سے ڈاکٹر صدیق خان شبلی (سابق ڈین کلیہ سماجی علوم ) کو فون کیااور انہیں بتایا کہ چشتی صاحب کو ڈگری ایوارڈ کر دیں، میں ان کے مقالہ سے مطمئن ہوں۔ فائل پر دستخط کر دوں گا۔
غازی صاحب کو اللہ جل شانہ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا، لیکن میں نے ان کی تین خصوصیات ایسی دیکھیں جن میں میرے تجزیہ کے مطابق ان کی کامیابی کا راز مضمر تھا :
آپ کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرماں بردار تھے۔ والدہ کی دُعا ئیں آپ کے ساتھ رہیں اور آپ نے ہمیشہ اپنی والدہ کو راضی رکھا۔
دوسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ قرآن مجید کا بہت اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ آپ کو جونہی موقع ملتا تھا، آپ اُسے قرآن کی تلاوت میں صرف کرتے تھے، یہاں تک کہ گاڑی میں سفر کے دوران بھی آپ تلاوت کرتے رہتے تھے۔
تیسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ مالی معاملات میں حد درجہ محتاط اور دیانت دار تھے۔
ڈاکٹر غازی کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ معمولی خلا نہیں۔ اس قحط الرجال کے دَور میں آپ کے وجود کی پہلی سے کہیں زیادہ ضرورت تھی، لیکن اللہ جل شانہ کا اپنا نظام ہے۔ اللہ جل شانہ کی مشیت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا انتقال آناً فاناً ہوا۔ ۲۶؍ ستمبر ۲۰۱۰ء کی صبح کو آپ نے عالم دُنیا کو خیر باد کہا ۔ نمازِ ظہر کے بعد نمازِ جنازہ ہوئی۔ نمازِ جنازہ میں اسلام آباد کے تقریباً تمام اہل علم شریک ہوئے۔ ہر شخص سوگوار تھا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تاحد نگاہ فضا پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ :
موت العالِم موت العالَم
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ - نشانِ عظمتِ ماضی
ڈاکٹر قاری محمد طاہر
لیجیے، ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی عالم بقا کو سدھارے۔ ۲۶ ستمبر ان کا یوم موعود تھا جو آن پہنچا۔ اس یوم موعود کی پہلے نہ ڈاکٹر صاحب کو خبر تھی نہ کسی اور کو۔ صرف داعئ اجل ہی کو علم تھا۔ یہ بھید اسی وقت کھلا جب داعئ اجل نے دستک دے دی۔ ڈاکٹر صاحب اٹھے اورچل دیے۔ کسی کو بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ کاش پہلے پتہ چل جاتا، لیکن اگر پہلے پتہ چل بھی جاتا تو بھی دنیا والے کیا کر لیتے۔ اس جہان میں ہر انسان تو بس بے بس ہی ہے۔
دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو اپنے بچوں کی فکر تھی نہ دوست احباب کی۔ دم واپسیں بس اتنا کہا: ’’کیا نماز کا وقت ہو گیا؟‘‘ ظاہر بین لوگوں نے کہا ، نہیں ابھی نماز میں بہت وقت باقی ہے۔ دیدۂ بینا بولی، ڈاکٹر صاحب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب رخصت ہوتے ہوئے پیغام دے گئے۔
فرصت کار فقط چار گھڑی ہے یارو
یہ نہ سمجھو کہ ابھی عمر پڑی ہے یارو
اس دنیا میں کسی کو دوام نہیں، اول فنا آخر فنا۔ جانا تو ہر ایک کو ہی ہے لیکن موت موت میں فرق ہے۔ موت اگر کسی کے آنگن میں آئے تو ایک ہی مرتا ہے لیکن فرشتۂ اجل اگر کسی نابغہ روزگار شخصیت کے دروازے پر دستک دے دے تو ایک نہیں پوری قوم کا جنازہ اٹھتا ہے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، اس حقیقت کا ادراک صاحبان بصیرت ضرور ہی رکھتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب حال کی آبرو اور ماضی کی عظمت کا نشان تھے۔ ان کو قدیم و جدید پر یکساں عبور تھا ۔ اردو انگریزی عربی بولتے تو محسوس ہوتا وہ زبان کے بندے نہیں بلکہ زبان ان کی باندی ہے اور الفاظ ان کے غلام جو صف بستہ ہاتھ باندھے حکم کے منتظر کھڑے ہیں۔ زبان کھولتے ہی علم کے موتی رولتے۔ سننے والے مبہوت ہو جاتے اور گفتگو سے گوہر چنتے تھے۔
یہ غالباً ۱۹۹۱ء کی بات ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سب سے پہلی ایم فل کی ورکشاپ تھی۔ اس ورکشاپ میں صوبہ سرحد اور پنجاب کے بیشتر حضرات شامل تھے۔ شاید ایک آدھ صاحب سندھ یا بلوچستان کے بھی ہوں ۔ یہ سب حضرات کالجوں کے لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ گویا سب کے سب کسی نہ کسی صورت میں پڑھے لکھے کہلاتے تھے۔ ورکشاپ کا اہتمام یونیورسٹی کی سابقہ عمارت میں کیا گیا تھا۔ اعلان ہوا کہ کل کا لیکچر ڈاکٹر محمود احمد غازی دیں گے۔ ہم اس وقت تک ڈاکٹر صاحب کے نام سے شناسا نہ تھے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کا نام پہلی مرتبہ ہی سنا تھا۔ بیشتر شرکا کی زبانوں پر ان کی عظمت کے تذکرے تھے۔ لہٰذا سبھی وقت مقررہ پر ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ دراز قد، فیروزی رنگ کا تھری پیس سوٹ، انتہائی سرخ ٹائی، سر پر قراقلی ٹوپی، لباس کی نفاست، آپ کی شخصیت میں خوب نکھار پیدا کر رہی تھی۔ چہرے پر لگی لگی داڑھی۔ مقدارِ داڑھی کو معیارِ اسلام سمجھنے والے حضرات کی جبین پر ’’؟‘‘ کا نشان واضح تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی عالمانہ فاضلانہ گفتگو نے سکہ جمالیا ۔ بعد میں نجی محفلیں جمیں تو بحث، موضوع بحث اور اندازِ تکلم پر ہی تھی۔ بعض حضرات نے ڈاکٹر صاحب کی داڑھی کے طول و عرض، یک مشت و چہار انگشت کو موضوع بنانا چاہا لیکن ان کی کسی نے نہ سنی، نہ بات کو بڑھایا۔ جہاں علم کا بحربے کنار ہو جائے، وہاں یہ بحثیں سطحی ہوتی ہیں۔ علم و عمل میں فاصلے نہ ہوں تو ظاہری تراش خراش کی حد بندیاں باقی نہیں رہتیں۔
یہ ہماری ڈاکٹر صاحب سے پہلی شناسائی تھی۔ جس نے ہمارے دل کو مٹھی بند کر لیا۔ گرفت اتنی پختہ کہ ان کی موت کے بعد اب تک ڈھیلی نہ ہوئی۔ اس کے بعد بیسیوں مرتبہ ملاقات کی مجلسیں جمیں ۔ ہمیشہ یہی لگا، وہ میرے اور ہم ان کے ہیں۔ میری گزارش پر کئی مرتبہ فیصل آباد تشریف لائے۔ ان کی طبیعت میں نہ تکلف تھا، نہ ہی وہ زیادہ رکھ رکھاؤ کے عادی تھے۔ ہمیشہ کھلے دل سے اس طرح ملتے جیسے بچپن کے شناسا ہیں۔ اپنائیت اتنی کہ لگتا گلی گلیان میں اکٹھے کھیلتے کودتے بڑے ہوئے ہیں۔ کبھی اپنے علم کا رعب نہ جمایا، نہ بڑھ کر اپنی ہی کہی ، بلکہ دوسرے کی پورے دھیان اور توجہ سے سنی، پھر اپنی کہی اور دلائل سے زیر کیا۔ اہل علم کی یہی پہچان ہوتی ہے، اسی چیز نے ان کو بڑا بنایا۔
آپ کے نام کے ساتھ غازی کا لاحقہ کیوں اور کیسے ہے؟ اس کا علم تو ہمیں نہیں ، ہم اتنا ضرور جاتے ہیں کہ آپ علم کے غازی ضرور تھے۔ کسی موضوع پر بحث میں آپ بڑے بڑے علماء پر غالب آتے تھے۔ یہ تغلب آواز کی بلندی سے نہیں علم کی گہرائی اور گیرائی سے پیدا ہوتا۔ آپ کی رائے مستحکم ہوتی جس پر نصوص کی تائید پیش کرتے تھے اور سامع کو قائل ہوتے ہی بنتی تھی۔
ایک مجلس میں اس عاجز نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات چھیڑی تاکہ ساز پر مضراب کی ضرب سے دھنیں جنم لیں اور موتیوں کی بارش ہو۔ میں نے مسئلہ تملیک کے بارے میں استفسار کیا۔ فرمانے لگے، تملیک صرف چار مدات میں ہے، دیگر میں نہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ علمائے احناف تو تملیک کو زکوٰۃ کا لزوم قرار دیتے ہیں ۔ فرمانے لگے، قرآن میں آٹھ مدات زکوٰۃ کا ذکر ہے جن میں سے پہلی چار میں تملیک ہے ، مؤخر الذکر چار میں تملیک نہیں ہے۔ میں نے دلیل پوچھی۔ فرمانے لگے ، پہلی چار میں لام تملیک ہے، آخری چار میں نہیں ہے۔
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِیْنِ وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْْہَا وَالْمُؤَلَّفَۃِ قُلُوبُہُمْ (۹:۶۰)
ان چاروں مدات میں لام تملیک ہے، لہٰذا ان میں تملیک لازم ہے، لیکن وَفِیْ الرِّقَابِ غلام کو آزاد کرایا جائے گا تو اس کی قیمت کی تملیک غلام کی نہیں بلکہ اس کے مالک کے لیے ہوگی۔ اسی طرح وَالْغَارِمِیْنَ میں تملیک مقروض کے لیے نہیں، قارض کی ہوگی۔ یہی کیفیت وَفِیْ سَبِیْلِ اللّہِ وَابْنِ السَّبِیْلِ میں ہے۔
آپ کا علمی قد کاٹھ بہت نہیں بلکہ بہت ہی بلند تھا جہاں پر پہنچنا ہر کہ ومہ کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ علم و عمل ہی انسان کو عزت بخشتا ہے۔ علم روشنی ہے، عمل راستہ۔ آپ کی گرفت دونوں پر یکساں تھی۔ عمل کے بغیر محض علم کبر لاتا ہے اور علم بغیر عمل راستہ کھوٹا کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس علم کی قندیل بھی تھی اور راستے کی معرفت بھی۔ اسی سبب آپ کی عزت و توقیر علمی حلقوں میں مسلم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ تواضع و انکسار کا مرقع تھے۔ کبھی خود کو بڑا خیال نہ کیا۔ ایک مرتبہ میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب! اگرچہ آپ کی شان سے تو کہیں فروتر ہے، لیکن آپ کی محبت کے پیش نظر جسارت کر رہا ہوں ۔ فیصل آباد میں دارِارقم نام کا چھوٹا سا سکول ہے ۔ اس کی سالانہ تقریب میں آپ کو مہمانِ خصوصی کی کرسی پر بٹھا کر اپنی اور سکول کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ فون سنتے ہی میرے جملوں پر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے: یہ اسکول کی نہیں، آپ میری عزت افزائی فرما رہے ہیں، میں ضرور آؤں گا۔ تاریخ کا تعین ہوگیا، میں نے عرض کی، اسلام آباد و فیصل آباد کے مابین ہوائی سروس نہیں ہے۔ آپ کو زحمت ہوگی، کار پر سفر کرنا ہوگا۔ فرمانے لگے، زحمت نہیں میرے لیے رحمت ہے۔ میں کار پر ہی آؤں گا۔ یوں بھی ہوائی سروس ہوتی تو بھی وقت تو یکساں ہی لگتا۔ ہوائی جہاز میں سفر کریں تو کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پہنچنے کے لیے گھر سے مزید ایک گھنٹہ قبل روانہ ہونا ضروری ہے۔ پھر فیصل آباد کے ہوائی اڈے سے کلیرنس اور اصل مقام تک پہنچنے میں گھنٹہ ڈیڑھ تو لگتا ہی ہوگا۔ اس طرح کم از کم پانچ گھنٹے تو صرف ہوں گے جبکہ موٹر وے سے ساڑھے تین گھنٹے لگیں گے۔ یہ سب تفصیل آپ کی فطری تواضع کا ثبوت تھی ، وگرنہ سکول کی تقریب میں نہ آنے کے لیے ہوائی سروس کی عدم موجودگی او رمصروفیت کا ذکر بڑے معقول بہانے بن سکتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے ہاں یہ تکلفات عنقا تھے۔ یہی ان کی عظمت تھی۔
تقریب سے ایک روز قبل میں نے یاد دہانی کے لیے فون کیا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی بولے، مجھے کل کی تقریب بالکل یاد ہے، میں فجر کی نماز کے ایک گھنٹہ بعد چلوں گا۔ میری ذہنی پستی، میں نے عرض کیا کہ دیر ہو جائے گی، آپ کے انتظار میں سامعین کو روکنا، بٹھانا ہمارے لیے مشکل پیدا کر دے گا۔ اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے فوری بعد سفر شروع کر یں تو ہمارے لیے سہولت رہے گی۔ آپ نے ایک منٹ توقف فرمایا اور بولے، اچھا ایسا ہی کروں گا۔ اگلے روز ہم موٹر وے پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ فون آیا: میں موٹر وے فیصل آباد انٹرچینج پر آپ کا منتظر ہوں۔ فون سنتے ہی بڑی خفت ہوئی۔ فوراً موٹر وے کی طرف بھاگے، گاڑی تیز دوڑائی، پھر بھی آدھ گھنٹہ صرف ہوگیا۔ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور ڈاکٹر صاحب اگلی سیٹ پر بیٹھے تلاوت کلام اللہ میں مصروف تھے۔ ہم نے معذرت کی۔ آپ آگے بڑھے ، منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا، معذرت کی ضرورت نہیں، مجھے فائدہ ہوگیا۔ منزل رہتی تھی، پوری کر لی۔
تقریب کے اختتام پر فرمانے لگے ، فیصل آباد میں بڑی عظیم شخصیات رہتی ہیں، میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ میں نے نام پوچھا۔ بولے، مولانا مجاہد الحسینی اسلاف میں سے ہیں، ان سے مل لیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو لے کر مولانا مجاہد الحسینی کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ وہ محبت سے اور ڈاکٹر صاحب عزت سے ملے۔ وہاں سے جامعہ امدادیہ چلے گئے، راستہ بھر مولانا کی خدمات کا تذکرہ کرتے رہے۔
خط کا جواب لکھنے کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب سخی نہیں بلکہ خط کے جواب کو لزوم کا درجہ دیتے۔ خط کا راقم چھوٹا ہو یا بڑا،اس سے غرض نہیں۔ اس نے سلام کے ذریعہ مخاطب کیا ہے، قرآن حکیم کے مطابق سلام کا جواب بھی لازم اور پوچھی گئی بات کا جواب بھی لازم ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:
وَإِذَا حُیِّیْْتُم بِتَحِیَّۃٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْہَا أَوْ رُدُّوہَا (۴:۸۶)
’’جب کوئی تمہیں سلام کرے تو جواب زیادہ احسن طریق سے دو یا اسی کو لوٹا دو۔ ‘‘
ڈاکٹر صاحب کے نزدیک خط کا جواب دینا بھی لازم تھا کہ اس میں لکھنے والا سلام ہی کرتاہے۔ دوسرا حکم بھی فرمانِ الٰہی ہے: فَاسْأَلُواْ أَہْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (۱۶:۴۳)۔
ڈاکٹر صاحب سے شناسا حضرات انہیں خط لکھتے، آپ ہر ایک کا جواب دیتے۔ ہماری دانست میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب نے قصداً میرے خط کا جواب نہیں دیا۔ یہ ان کا بڑا وصف تھا۔ اکابر کا معمول بھی یہی رہا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے حالات و معمولات میں بھی اس بات کی پابندی ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب عموماً جواب ہاتھ سے لکھتے۔ کبھی کمپوزنگ یا ٹائپ سے بھی کام لیتے، لیکن عموماً ہاتھ سے جواب لکھنے کی عادت تھی۔ مجھ سے کوتاہ علم اور کوتاہ عمل کے ساتھ بھی اس معاملے میں ان کا معمول سخیانہ تھا۔ میں نے جب بھی لکھا، جواب سرعت سے آیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح مطلوب کی معمولی طلب پر طالب لپکتا ہے۔ یہ بات ان کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک تھی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی طرف سے لکھے گئے خطوط تحقیق کا مستقل علمی عنوان ہے جس سے بہت سے علمی گوشے منکشف ہو سکتے ہیں۔ شاید کوئی غواص اس علمی سمندر میں اترے اور علمی موتی چنے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ علمی میدان کے شناور تھے۔ پڑھنا لکھنا، زبان کے ذریعے علم کے موتی بکھیرنا ہی ان کا مشغلہ تھا۔ یہ پرویز مشرف کا زمانۂ اقتدار تھا کہ اچانک خبر ملی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کو وفاقی حکومت میں وزارت کا قلمدان پیش کیا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس قلم دان کو سنبھال لیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ پہلی خبر تک تو کسی کو حیرت نہ ہوئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ ان سے حکومتی سطح پر کوئی اہم خدمت لی جائے۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے کرسی وزارت کی پیشکش باعث حیرت نہ تھی، لیکن دو سری خبر کہ ’’آپ نے وزارت کی ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں اور بطور وزیر وفاق حلف اٹھا کر کام بھی شروع کر دیا‘‘، اس پر علمی حلقوں میں اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی افتاد طبع اس عہدہ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لیکن یہ امر واقع تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے اس عہدہ سے فارغ ہوئے تو عقدہ کھلا اور وہ مصلحت سامنے آئی جس کے لیے آپ نے اپنی طبیعت کے برعکس سیاست جیسی پرخار وادی میں قدم رکھنا گوارا کر لیا۔
یہ وہ دور تھا کہ جب مدارس کو ختم کرنے یا ان کو حکومتی احکامات کا تابع بنانے کی بھرپور مہم چل رہی تھی اور پرویزی حکومت کے بارے میں یہ حقیقت سامنے آچکی تھی کہ وہ کتوں سے محبت رکھتی ہے اور مصطفےٰ کمال پاشا مشرف کے آئیڈیل ہیں، اسی آئیڈیلزم کے اشتراک کے سبب مشرف حکومت بھی دین سے ہمدردی رکھنے والوں کو نظر بد سے دیکھتی ہے۔ ان معروضی حالات میں ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اپنی طبیعت پر جبر کیا اور مدارس کو حکومتی چیرہ دستی سے بچانے کے لیے وزیر مذہبی امور بنے اور مدارس کے دفاع میں کامیاب رہے۔ جب یہ کام ہو چکا تو آپ قلیل عرصہ ہی میں بغیر وجہ بتائے یا بغیر کسی ظاہری سبب کے اس منصب سے علیحدہ ہو گئے۔
وزارت سے علیحدگی کے بعد میری ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہوئی۔ میں نے اصل مقصد کو سمجھنے کے باوجود ڈاکٹر صاحب سے چٹکی لی۔ عرض کی، ڈاکٹر صاحب! آپ تو سیاسی ہو گئے۔ میرا سوال نما تبصرہ سن کر بولے، ہرگز نہیں ، میں تو بازارِ سیاست سے بس گزرا ہوں۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ اگر ڈاکٹر صاحب مرحوم اس وقت اس پرخار وادی میں قدم نہ رکھتے تو مدارس اور دینی تعلیم کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا اور مدارس کے مہتمم حضرات اہتمام سے فارغ بیٹھے ہوتے۔ جبہ بچتا نہ دستار، نہ ہی کھالیں ملتیں بلکہ کھالیں نوچ لی جاتیں۔ ڈاکٹر صاحب پر زبان طعن دراز کرنے والوں کی زبانیں کھنچ چکی ہوتیں۔
یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مشرف دور میں دینی مدارس کے خلاف اٹھنے والے طوفان کو روکنے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت صرف اور صرف ڈاکٹر محمود احمد غازی ہی کی تھی جو قدیم و جدید تمام علوم کی جامع تھی۔ ڈاکٹر محمود غازی واحد شخصیت تھے جو منہ ٹیڑھا کرکے انگریزی بولنے والوں کو مسکت جواب دینے کی اہلیت کے حامل بھی تھے اور ساتھ ہی دینی علوم کی اتھاہ گہرائیوں پر پوری نظر رکھتے تھے اور اس معاملے میں کسی سمجھوتے کے قائل نہ تھے۔ آپ نے اسی زمانے میں مدارس میں رائج نصاب میں معروضی حالات کے تقاضوں کے مطابق قدیم و جدید کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور اپنے قلیل دورِ وزارت میں مدارس کے لیے نہایت اہم نصاب مرتب کیا، لیکن افسوس بعض دینی حلقوں نے ڈاکٹر صاحب کے اس دانش مندانہ فعل کو بھی اپنی ذہنی اپج اور مخالفت برائے مخالفت کے جذبے ہی سے لیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایسے حضرات کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اپنا مشن جاری رکھا۔ جب ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اس نصاب کا اعلان ہوا تو راقم نے انہیں ایک خط لکھا جس میں مشورہ دیا کہ آپ بہت اہم کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن براہ کرم کوئی ایسی سبیل بھی تلاش کیجیے کہ علما کا روایتی طبقہ آپ کے خلاف صف آرا نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی مثبت مساعی علما کے منفی رویے کا شکار ہو جائیں۔ اس خط کا آپ نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مجھے جتنے خطوط موصول ہوئے، ان میں صرف یہی ایک خط ہے جو کمپوز شدہ ہے۔ یہ خط انہوں نے اپنی وزاایک رت کے دوران اپنے پرنسپل سیکرٹری سید قمر مصطفےٰ کی طرف سے لکھوایا، وگرنہ باقی دیگر تمام خطوط ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا:
’’ڈاکٹر غازی صاحب نے آپ کے مراسلے اور ماہنامہ التجوید کے شمارے کا شکریہ ادا فرمایا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ میں آپ کو مطلع کروں کہ ماڈل دینی مدارس کا نصاب مختلف علماء کرام اور وفاق کے نمائندوں کی مشاورت سے ہی مرتب کیا جا رہاہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس نصاب سے مطلوبہ اہداف کا حصول ممکن ہو سکے گا‘‘۔
ڈاکٹر صاحب کو اپنے علم پر کبھی ناز ہوا ہی نہیں۔ کبھی کسی علمی موضوع پر بحث و تمحیص میں اپنی علمیت کو فخر کے انداز میں بیان نہ کرتے بلکہ اپنے سے کم علم آدمی کی بات کو بھی اس طرح سنتے جیسے اس معاملے میں بالکل بے خبر ہیں۔ یہ آپ کی عالی ظرفی کی علامت تھی۔ اسی طرح وزارت کے منصب پر فائز ہوئے تو عاجزی و انکساری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کی وزارت ہی کے ایام کا واقعہ ہے کہ راقم کو آپ کی طرف سے کتابوں کا بنڈل بذریعہ ڈاک موصول ہوا۔ باہر وزارت حج و اوقاف کی مہر موجود تھی۔ میں نے بنڈل کھولا ، اس میں کچھ اہم علمی کتب تھیں۔ ساتھ ہی آپ کا خط تھا ۔ لکھا تھا کہ حج کے دوران مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ جانا ہوا۔ مہتمم مولانا حشیم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یہ کتب بھیجنا تھیں۔ وہ متردد تھے کیسے بھیجوں۔ میں نے کہا مجھے دے دیں ، میں پاکستان جاکر پہنچا دوں گا۔ مجھے کتابیں وصول کرکے خوشی ہوئی اور اس سے زیادہ خوشی اس خط کو پڑھ کر ہوئی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کس قدر متواضع اور منکسرالمزاج ہیں جو اہل علم کاخاصہ ہے۔ میں نے شکریے کے طور پر فون کیا تو فرمانے لگے، شکریے کی کیا بات ہے ۔ میں آ ہی رہا تھا اور میں نے کتابیں خود تھوڑے اٹھانا تھیں۔ سامان میں آگئیں، ڈاک سے آپ کو پہنچ گئیں۔ پھر کہنے لگے ، ان کتابوں کے مطالعے سے آپ کو جو فائدہ ہوگا تو اس ثواب کا کچھ حصہ میرے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اب وہ دنیا میں نہیں لیکن ان کے ان جملوں کی حلاوت میرے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ میرا شعور اور لاشعور دونوں بین کرتے ہیں۔ کاش جیتا کوئی دن اور، کاش موت کا فرشتہ ڈاکٹر صاحب کا گھر بھول جاتا اور اسلام آباد کے پہاڑی سلسلہ میں گم ہو کر خائب و خاسر ہی لوٹ جاتا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ، فرشتۂ اجل بھی ویفعلون مایؤمرون (۶۶:۶) کا پابند ہے۔
۲۰۰۱ء میں آپ وزیر مذہبی امور تھے۔ سرکاری منصب کے حوالے سے حج وفد کی سربراہی آپ کے سپرد تھی۔ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمارے ایک دوست مصباح الحق صدیقی صاحب ، جو نیشنل بنک میں آفسر ہیں، بھی اس سرکاری وفد میں شامل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز وضو اور حوائج ضروریہ کی تکمیل کے لیے سب لوگ قطار بنائے باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو بھی قطار میں لگے انتظار کرتے دیکھا۔ میں ان سے آگے تھا، ڈاکٹر صاحب تین چار افراد کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے احتراماً عرض کی ، آپ مجھ سے آگے تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے شکریہ ادا کیا اور اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے، آگے نہ بڑھے۔ میں ان کی یہ تواضع و انکساری اور اصول کی پابندی دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کی کہ ڈاکٹر قاری محمد طاہر مدیر التجوید میرے دوست ہیں۔ ان کے حوالے سے آپ سے ملنا چاہتا ہوں ، وقت دے دیجیے۔ خندہ پیشانی سے بولے، میرے خیمہ کا نمبر یہ ہے۔ آپ جس وقت چاہیں تشریف لائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر ان کے خیمہ کی طرف چل دیا۔ آپ تلاوت کلام اللہ میں مشغول تھے۔ میں پیچھے بیٹھ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو مجھے دیکھا ، بہت ہی خوشی سے میرا استقبال کیا۔ میرے ہاتھ میں آپ کا کتابچہ بعنوان آسان حج پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کتابچہ لیا ، کچھ ورق گردانی کی۔ فرمایا بہت مختصر اور مفیدہے۔ انہوں نے از خود تعریفی کلمات اس کتابچہ پر تحریر کر دیے۔ واپسی پر مصباح الحق صدیقی صاحب نے وہ کتابچہ مجھے لا کر دیا اور سارا واقعہ بھی سنایا۔ میرے دل میں ڈاکٹر صاحب کی عظمت مزید ہوئی۔ آپ کس قدر تعلق خاطر کو نبھانے والے ہیں۔ آپ کی وہ دو سطریں راقم کے پاس محفوظ ہیں اور میرے لیے سرمایہ حیات کا درجہ رکھتی ہیں۔
کوئی شخص فقیر ہو یا امیر، عالم ہو یا صوفی، بادشاہ ہو یا گدا، سب کا حاصل حیات گور کے علاوہ کچھ نہیں ۔ جو آیا جانے ہی کے لیے، رہنے کے لیے تو کوئی آتا ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی کی اسی حقیقت سے پردہ سرکایا ہے۔
بادشاہوں کی بھی کشت عمر کا حاصل ہے گور
جادۂ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور
بادشاہ و امراء دنیا میں زر و زمین چھوڑ جاتے ہیں جن پر بعد والے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ قتل و غارت اور خون ریزی سے بھی گریز نہیں کرتے لیکن علماء کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ فرمان رسول ہے: العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علما، انبیا کے وارث ہیں۔ انبیا کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، ان کا ترکہ علم ہوتا ہے۔ زندہ رہیں تو علم کی میراث تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوں تو ترکہ میں بھی علمی وراثت ہی ہوتی ہے جس سے ایک زمانہ صدیوں کسب فیض کرتا ہے۔ امام غزالی ایران کے شہر طوس میں محو استراحت ہیں۔ آپ کو رخصت ہوئے صدیاں بیتیں لیکن ان کی کیمیائے سعادت روشنی بکھیر رہی ہے۔ بہت سے غیر مسلم کیمیائے سعادت کو پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سعید ارواح اس سے علمی کیمیا گری کے اصول حاصل کر رہی ہیں۔ امام الہند شاہ ولی اللہ مہندیاں دہلی میں آسودہ خاک ہیں لیکن حجۃ اللہ البالغہ سے پوری دنیا میں اہل علم من کی دنیا کو اجال رہے ہیں اور تاقیامت اجالتے رہیں گے۔
اسی طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی کی پاکیزہ روح بھی جلد ہی عالم ارواح کو سدھار گئی۔ اسلام آباد کی مٹی نے ان کے جسم کو پناہ دے دی۔ وہ یقیناًمٹی تلے آسودۂ رحمت ہیں لیکن وہ اپنے قلم سے اتنا کام ورثہ کے طور پر چھوڑ گئے ہیں کہ ان کے قلم سے نکلی تحریریں بہت سے کم علموں کو علم کی مالاؤں سے آراستہ کرتی رہیں گی۔ ان کی ایک ایک کتاب ہی پی ایچ ڈی کے لیے مستقل عنوان ہے۔ دورِ حاضر میں ذہن بنجر ہو گئے ہیں۔ تحقیق کے لیے عنوانات تلاش کرنا بھی کارے دارد، لیکن ڈاکٹر غازی کی کتابیں اور تحریریں غواص حضرات کو مزید راہیں عطا کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی کی قلمی میراث میں محاضرات قرآنی، محاضراتِ حدیث، محاضراتِ فقہ، قانون بین الممالک، اسلام اور مغرب تعلقات، مسلمانوں کا دینی و عصری نظام تعلیم، اسلامی بنکاری: ایک تعارف، قرآن مجید:ایک تعارف انتہائی اہم ہیں۔ ان میں سے ہر تحریر مستقل موضوع ہے، جس کو بنیاد بنا کر علم و تحقیق کے شناور مزید گوہر تابدار تلاش کر سکتے ہیں۔ ان کتب کے علاوہ ملکی و غیر ملکی جرائد میں طبع ہونے والے مضامین تحقیق کے لیے مستقل موضوع ہیں جن سے طلبہ اپنی پیشانیوں پر پی ایچ ڈی کے تمغے سجا سکتے ہیں جس سے ان کا دسترخوان بھی بابرکت ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے جہاں تحریر کا ملکہ دیا، وہاں تقریر کا ملکہ بھی وافر عطا کر رکھا تھا۔ ان کی ہر تقریر کئی کتب پر بھاری ہوتی۔ بولتے تو محسوس ہوتا کہ علم کا بحرِ بے کراں ہے، سننے والوں کا دامن موتی سمیٹنے سے کوتاہ نظر آتا۔ دورانِ تقریر امہات الکتب سے ایسے ایسے حوالے پیش کرتے جیسے موسوعہ کھل جائے۔
ڈاکٹر صاحب دھیما مزاج رکھتے تھے۔ ہمیشہ خوش رہتے ، خوش رکھتے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہیں ایک مرتبہ غصہ میں بھی دیکھا لیکن عام لوگوں کی طرح وہ غصہ میں غضبناک نہ ہوتے۔ ۲۰۰۷ء کی بات ہے، مشرف صدر تھے۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کا ڈول ڈالا۔ ان کا خیال تھا کہ مختلف مذاہب کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ مختلف مذہب رکھنے والے لوگوں خصوصاً عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ مستحکم ہو اور ہم پوری دنیا خصوصاً امریکہ کو باور کرا سکیں کہ ہم میں اور عیسائیت میں ہم مشربی ہے۔
اس مقصد کے لیے صدر صاحب نے اسلام آباد میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جس میں پاکستان بھر سے تقریباً دو ڈھائی سو کے قریب علماء کو اکٹھا کیا گیا۔ پاکستان کے چوٹی کے عیسائی بشپ اور فادر وغیرہ بھی بلائے گئے۔ ایک آدھ ہندو اور سکھ پیشوا بھی شریک ہوئے۔ کراچی سے مولانا تقی عثمانی ، مولانا قاری محمد حنیف جالندھری، اسی مقام کے شیعہ حضرات بھی شریک ہوئے۔ راقم بھی مدعوین میں سے تھا۔ صدر مشرف نے صدارت فرمائی۔ مولانا فضل الرحیم جامعہ اشرفیہ نے مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم کی لے میں تلاوت کی اور تعالوا الی کلمۃ سواء بینا و بینکم (۳:۶۴) کی آیات پڑھیں۔ علماء کرام اور عیسائی پیشواؤں نے اسلام اور عیسائیت کے فضائل بیان کیے۔ علماء کرام نے اسلام کو عیسائیت کے قریب اور عیسائیوں نے عیسائیت کو اسلام کی اصل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حسب معمول انتہائی پر تکلف چائے پر اجلاس ختم ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب سے ملنے کی غرض سے ان کے دفتر گئے۔ جو فیصل مسجد سے متصل تھا۔ ڈاکٹر صاحب حسب عادت و حسب معمول انتہائی تپاک ، محبت اور خوش روئی سے ملے۔ اسلام آباد آنے کی غرض پوچھی۔ میں نے بین المذاہب ہم آہنگی اجلاس کی روداد سنائی۔ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ پر ملال ہوا۔ بولے عقیدہ توحید و تثلیث میں مماثلت کس طرح ممکن ہے؟ میرے دورِ وزارت میں بھی ایسی کوشش ہوئی تھی، میں آڑے ہی آیا جس پر حاملین تثلیث ناراض ہوئے۔ ہمیں اللہ کی رضا جوئی مقصود ہونی چاہیے۔ حالات کیا رخ اختیار کریں ، اس سے غرض درست نہیں۔ ڈاکٹرصاحب کا لہجہ سخت تھا۔ مجھے احساس ہوا ایں گناہ ہست کہ من ہم کردم ۔ کئی روز دل کچوکے لگاتا رہا۔
عالمی رابطہ ادب اسلامی، ادبا کی ایک تنظیم ہے جس کی بنیاد عالم اسلام کے نامور عالم، مؤرخ ، ادیب، متصوف بزرگ سید ابو الحسن علی ندوی نے رکھی تھی۔ آپ عالمی رابطہ ادبِ اسلامی پاکستان کے رکن تھے۔ آپ کے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے اس کا رکن ہونا آپ کے لیے کوئی بڑے اعزاز کی بات نہ تھی بلکہ آپ کی رکنیت عالمی رابطہ ادب اسلامی کے لیے باعث عزت و افتخار تھی۔ لیکن جب بھی آپ سے ا س حوالے سے ملاقات ہوئی، ہمیشہ یہی فرمایا کہ اس تنظیم کا رکن ہونا میرے لیے اعزاز و فخر کی بات ہے۔ راقم اس تنظیم کا جنرل سیکرٹری تھا۔ اس حوالے سے مجھے ہمیشہ بہت عزت عطا فرمائی۔ میری ادارت میں ’’اخبارِ رابطہ‘‘ کا اجرا ہوا۔ اس کا پہلا شمارہ شائع ہوا تو میری حوصلہ افزائی کی اور بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ فرمانے لگے ، اگر آپ کی یہ کوشش مسلسل جاری رہی تو رابطہ ان شاء اللہ بہت ترقی کرے گا۔ اہل علم سے رابطہ کرنے میں سہولت بھی ہوگی اور رابطہ کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہی رابطہ میں تحریک کا سبب بنے گی۔
رابطہ کے بعض عہدیداران کو وہم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب رابطہ کے صدر بننے کی خواہش رکھتے ہیں حالانکہ امر واقعہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے رابطہ کا صدر ہونا قطعاً خواہش کی بات نہ تھی۔ وہ اس عہدہ سے کہیں بڑے تھے۔ آپ کو اس کی خبر ملی تو مسکرائے اور اتنا فرمایا کہ میں تو صرف اس لیے اس کا رکن ہوں کہ مولانا ابوالحسن علی ندویؒ نے مجھے از خود اس کا رکن نامزد کر دیا تھا۔ یہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے ۔ وگرنہ میں نے ان کے جملے سنے اور محسوس کیا کہ زبان سے نہیں بلکہ حال سے فرما رہے ہیں۔
سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری
کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے
سچی بات ہے کہ ڈاکٹر محمود غازی کا وجود رابطہ ادب اسلامی کے لیے عزت و افتخار کا سبب تھا، وگرنہ ڈاکٹر صاحب موصوف اس قسم کے اعزازات سے ارفع و اعلیٰ تھے۔ یہ غالباً ۲۰۰۴ء کی بات ہے۔ میں اس وقت عالمی رابطہ ادب اسلامی پاکستان کا جنرل سیکرٹری تھا۔ مولانا فضل الرحیم اس کے صدر تھے۔ مجلس شوریٰ میں یہ بات طے ہوئی کہ مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کے حوالے سے بین الصوبائی سطح پر سیمینار منعقد کیا جائے جو اسلام آباد میں ہو۔ اس سیمینار کے ابتدائی انتظامات کے حوالے سے میرے ذمہ یہ خدمت لگائی گئی کہ میں اسلام آباد جاکر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کروں اور سیمینار کے لیے جگہ اور تاریخوں کا تعین کروں۔ میں اسلام آباد گیا، ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے مدعا عرض کیا، خوش ہوئے۔ فرمانے لگے، اس نیک کام کے لیے اسلامی یونیورسٹی کے ہال کو رابطہ والے اگر قبول کریں تو اعزاز ہوگا۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ میں خوشی سے دل ہی دل میں اچھل پڑا، لیکن میں نے اپنی خوشی چھپائے رکھی، ظاہر نہ ہونے دیا اور عرض کیا کہ آپ کی پیش کش اپنی جگہ، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لاہور جاکر دوستوں سے عرض کروں گا۔ جو فیصلہ ہوگا، آپ تک پہنچا دوں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی عظمت تھی۔ فرمانے لگے، مولانا فضل الرحیم صاحب کے سامنے میری پیشکش رکھیں، وہ ان شاء اللہ مان جائیں گے۔ مجھے حوصلہ ملا تو میں نے دست طمع دراز کیا۔ عرض کی ، ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اس پیشکش کو قبولیت ملے تو آپ رابطہ کے ساتھ مالی معاونت کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میری اندرونی کیفیت کو بھانپ گئے۔ میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا ، زیرلب مسکرائے۔ اب مجھ سے ضبط نہ ہوا، میرے حسن طلب کے جذبات چہرے اور آنکھوں سے ہویدا ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب بھی کھل کر ہنس دیے۔ فرمانے لگے، ہال کا خرچ، بجلی پانی کا خرچ اور تقریب کے بعد کھانا سب اسلامی یونیورسٹی برداشت کرے گی اور سامعین کی کمی بھی پوری کر دے گی۔ ساتھ ہی فرمانے لگے ، اب تو شوریٰ سے منظوری کی ضرورت نہ ہوگی! میں نے چٹکی لی، عرض کیا: آپ عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بڑے قدر آور رکن ہیں۔ آپ سے مشورے کے بعد کسی اور کے مشورے اور منظوری کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہم دونوں اس مکالمے کا حظ کافی دیر تک لیتے رہے۔
اس جگہ ایک انتہائی اہم واقعہ کا تذکرہ بہت ضروری ہے جو غازی مرحوم کے حوالے سے قوم کی امانت ہے۔ مقررہ تاریخوں پر مذکورہ سیمینار اسلامی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ ایک اجلاس کی صدارت ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فرمائی۔ اپنے خطبہ صدارت میں آپ نے مولانا ابوالحسن علی ندوی کے حوالے سے انتہائی اہم بات ارشاد فرمائی۔ میری دانست میں یہ بات پوری پاکستانی قوم کی امانت ہے جس کا ذکر اس جگہ بہت ضروری ہے۔ شاید اس بات سے ہمارے سیاست کار اپنا قبلہ درست کر سکیں اور حق و باطل میں امتیاز کی لکیر کھینچنے کا حوصلہ حاصل کریں۔
ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں صورت حال مخدوش ہے۔ اس کا تدارک ضروری ہے۔ مولانا ندوی اس خواب کی تعبیر و توضیح پر سوچ بچار کرتے رہے۔ ان کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ خواب اہم ہے اور انتظامی معاملہ ہے۔ اس کی اطلاع پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کو کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر آپ فوراً کراچی پاکستان تشریف لائے اور اس وقت کے وزیر قانون اے کے بروہی سے رابطہ کیا اور کہا کہ میری ملاقات فوراً جنرل محمد ضیاء الحق سے کرانے کا بندوبست کریں۔ بروہی صاحب نے ضیاء الحق سے رابطہ کیا اور مولانا ندوی کا پیغام پہنچایا۔ ضیاء الحق مرحوم نے کہا کہ مولانا عالم اسلام کے بڑے مفکر ہیں، انہیں اسلام آباد آنے کی زحمت نہ دیں۔ میں فوراً ان کی خدمت میں کراچی حاضر ہو رہا ہوں۔ جنرل مرحوم اسی وقت عازم کراچی ہو گئے۔ مولانا سے ملاقات ہوئی۔ ندویؒ نے اپنا خواب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ضیاء الحق کو بتلایا۔ غازی صاحب کے بقول خواب بیان کر چکنے کے بعد مولانا ندویؒ اپنی نشست سے اٹھے اور ضیاء الحق کی قمیص کا کالر پکڑا اور فرمایا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں بری الذمہ ہوں۔ اس موقع پر ڈاکٹر غازی صاحب کی آواز بھرا گئی۔ کہنے لگے ، یہ خواب سن کر ضیاء الحق مرحوم رونے لگے اور مولانا سے قدرے توقف سے بولے، مولانا! اب اگر ایسی صورت پیش آئے تو میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجیے گا کہ پاکستان کی فوج کا ہر جوان مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کٹ مرے گا۔ مدینہ منورہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ان شاء اللہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر غازی صاحب کی زبان سے یہ ساری بات سن کر پورے مجمع پر رقت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جنرل مرحوم نے جو اقدامات کیے، وہ اس وقت کے اخبارات کا حصہ ہیں۔
ڈاکٹر صاحب عالمی شہرت رکھتے تھے۔ پورا عالم اسلام ان کا قدر شناس تھا۔ ان کی آواز میں وزن تھا۔ عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بزرجمہر اگر چاہتے تو ڈاکٹر صاحب کے مرتبہ و مقام سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ اپنی ذات کے ہالے میں گم رہنے والے حضرات کی کوتاہ فکری نے فکر ندوی کو محدود رکھنے میں عافیت تلاش کی اور ’انا ولا غیری‘ کے جذبے کے تحت ادیبوں کو اس تنظیم سے اور اس تنظیم کو ادیبوں سے دور رکھنے کی شعوری کوشش میں کامیاب رہے، اسی لیے اہل بصیرت عالمی رابطہ ادب اسلامی کو عارفی رابطہ ادب اسلامی کہہ کر حظ لیتے ہیں۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی زاہد تھے، لیکن خشک ہرگز نہ تھے۔ آپ کی طبیعت شگفتہ تھی۔ علمی لطائف سے دوران گفتگو رنگ بھرتے تھے۔ سننے والا محظوظ ہوتا۔ میرے ہمراہ مولانا مجاہد الحسینی سے ملنے گئے تو بات تبلیغی جماعت کے حوالے سے چلی۔ فرمانے لگے، مولانا الیاسؒ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے میواتیوں کو مسلمان کیا جبکہ آج کل تبلیغی جماعت والے مسلمانوں کو میواتی بنا رہے ہیں۔
ان کے ہمراہ ایک مرتبہ واش بیسن پر وضو کرنا مجبوری بن گیا۔ میں نے عرض کی اس معاملے میں اہل حدیث حضرات کے مزے ہیں۔ جرابوں پر مسح کرکے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ پاؤں اٹھانا، سنک میں رکھنا ، اس مشکل سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ فرمانے لگے ، یہ بات درست ہے۔ مجھے اس کا تجربہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ایک غیر ملکی سفر میں ہوا جب میں نے ایک ہوائی اڈے پر وضو کے لیے واش بیسن کا رخ کیا۔ جب حسب عادت منہ اور بازو دھونے کے بعد پاؤں دھونے کی غرض سے ٹانگ پکڑی اور پاؤں واش بیسن میں رکھا تو ایک غیر ملکی نے میری اس حرکت کو بنظر حقارت دیکھا۔ اس وقت مجھے جرابوں پر مسح کر لینے کی رخصت کی اہمیت کا پتہ چلا۔ میں نے ازراہ استفسار پوچھا کہ پاؤں پر مسح کرنے کے لیے موزے کی شرائط کیا ہیں؟ فرمانے لگے، چار شرائط ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، ہم نے تو تین پڑھی ہیں، چوتھی شرط کون سی؟ فرمانے لگے، پہلی شرط یہ کہ تین چار میل چلے تو پھٹے نہیں۔ دوسرے یہ کہ موسمی اثرات سے محفوظ رکھے۔ تیسرے یہ کہ پاؤں پانی میں ڈالیں تو پانی جلد تک سرایت نہ کرے۔ مسکرا کر فرمانے لگے: اور چوتھی یہ کہ اس وقت کوئی حنفی مولوی صاحب پاس نہ ہوں۔
ایک مرتبہ ہم نے عالمی رابطہ ادب اسلامی کے تحت فیصل آباد میں سیمینار منعقد کرایا۔ ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی، آپ تشریف لائے۔ بڑی علمی گفتگو فرمائی۔ واپسی پر میں نے کچھ رقم سفر خرچ کے طور پر مصافحہ کرتے ہوئے پیش کرنا چاہی تو انکاری انداز میں بولے، بھئی یہ کیا سلسلہ ہے؟ میں نے عرض کی، بس قبول کر لیجیے تو زور سے بولے، آخر کس سلسلے میں؟ کوئی سلسلہ تو بتاؤ۔ میں نے فوراً عرض کی ، جناب یہ سلسلہ چشتیہ قادریہ نہیں بلکہ سلسلہ مالیہ ہے۔ میرے اس جواب پر ڈاکٹر صاحب بڑے محظوظ ہوئے اور خوب مسکرائے۔
ڈاکٹر صاحب عموماً موبائل فون نہیں رکھتے تھے۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن ہمارے پاس ان کا موبائل نمبر ہی نہ تھا۔ خیال ہوتا کہ اب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوگی تو موبائل نمبر لے کر لکھ لوں گا، لیکن ہر ملاقات پر ایسا کرنا بھول جاتا تھا۔ ایک روز یاد آہی گیا، ہم نے مطالبہ کیا، ڈاکٹر صاحب اگر پسند فرمائیں تو موبائل نمبر دے دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تو موبائل فون رکھتا ہی نہیں۔ ہم نے فوراً تعجب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب ہمیں ما اور لمَ کا حق تو نہیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اجازت دیں تو پوچھ لوں کہ آپ نئی ایجادات سے کیوں بدکتے ہیں؟ آپ نے موبائیل فون کیوں نہیں رکھا؟ ڈاکٹر صاحب نے بات سنی اور بغیر کسی توقف کے فرمانے لگے: إِثْمُہُمَا أَکْبَرُ مِن نَّفْعِہِمَا (۲:۲۱۹)۔
گویا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ہنسایا اور چپ بھی کرا دیا۔ میں نے جواب سنا تو خوب لذت لی۔ جب بھی ان کا جواب ذہن میں آتا ہے، بڑا حظ ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اس جملے نے ذہن کی تاروں کو چھیڑا تو ہم نے موبائل کے عنوان سے کالم لکھا۔ جس کے مندرجات یہ تھے:
’’ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمارے ملک کے نامور معروف دانشور ہیں۔ ان کا شمار ان اہل علم میں ہوتا ہے جو قدیم وجدید علوم کا ادراک رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے اہل علم ہمارے ملک میں خال خال ہی ہیں۔ وہ مرکزی حکومت کے سابق وزیر مذہبی امور بھی رہ چکے ہیں۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے چیف بھی رہے۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں جن کو یہ عہدہ تفویض ہوا۔ علمی اعتبار سے ان کی پذیرائی نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون پاکستان دیگر ممالک میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے تعلیمی اداروں کی اعلیٰ سطحی علمی کانفرنسوں میں ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان سے علمی موضوعات پر مقالات لکھنے اور پڑھنے کی فرمائش کی جاتی ہے۔ اردو کے علاوہ عربی اور انگریزی زبان میں تحریر و تقریر کا یکساں ملکہ رکھتے ہیں۔ اس وقت تک بہت سی کتب ان کے قلم سے نکلیں اور اہل علم کے لیے مزید علم کا ذریعہ بنیں۔ تواضع اور انکسار کا پیکر ہیں۔ لباس کے اعتبار سے بھی قدیم و جدید کا سنگم ہیں۔ تھری پیس سوٹ ، ہم رنگ نک ٹائی کے ساتھ ساتھ مشرقی لباس سے بھی جسم کو مزین کرتے ہیں۔ شلوار قمیص اور جیکٹ بھی زیب تن کرتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف علم ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ لباس کے اعتبار سے بھی قدیم و جدید کا سنگم ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ دورِ جدید کی اہم ترین ایجاد موبائل فون کو کبھی استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی موبائل اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا ’’ڈاکٹر صاحب! آپ کا موبائل نمبر کیا ہے‘‘؟ فرمانے لگے ’’میں موبائل رکھتا ہی نہیں‘‘۔ میں نے حیرت سے دوسرا سوال کیا ’’کیوں‘‘؟ تو ان کا جواب استعاراتی تھا جس سے وہی لوگ لذت لے سکتے ہیں جو اس آیت کے مطلب، مفہوم اور تناظر سے واقف ہیں۔ فرمانے لگے: ’’إِثْمُہُمَا أَکْبَرُ مِن نَّفْعِہِمَا‘‘۔ ترجمہ : ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدہ سے زیادہ ہے۔ ‘‘
اس کالم کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں خط لکھا جس کے مندرجات اس طرح ہیں:
’’برادرِ مکرم و محترم جناب ڈاکٹر قاری محمد طاہر صاحب
یقین جانیے کہ آپ کا ممدوح اتنی تعریفوں کا مستحق نہیں ہے جتنی آپ کے مضمون میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ محض کسر نفسی یا تواضع نہیں ، اظہارِ حقیقت ہے۔ آپ کا رسالہ ملتا رہتا ہے۔ استفادہ کرتا ہوں اور دعاگو رہتا ہوں۔ تجوید کے فنی مباحث تو میرے معیار تلاوت سے بلند ہوتے ہیں، ان سے استفادہ کا تو میں اہل نہیں ہوں، البتہ قراء حضرات کا تذکرہ دلچسپی سے پڑھتا ہوں۔ فن قراء ت کے حوالہ سے بطور لطیفہ کے عرض ہے کہ ۱۹۶۲ء میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ کے حکم سے مجھے تجوید میں سو میں سے ایک سو پانچ نمبر ملے تھے، لیکن اس حرکت کے ذمہ دار مولانا نہ تھے، کچھ حاسدین تھے۔
(قدرے دخل در معقولات: مصر کے مفتی اعظم کا نام علی جمعہ ہے اور ان کا خطاب جامعۃ الاسکندریہ میں ہوا تھا)
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی‘‘
یہ خط ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جو راقم کے پاس محفوظ ہے۔ اس خط سے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی بہت سی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں زہد کی خشکی نہ تھی بلکہ آپ شگفتہ طبیعت کے مالک تھے اور خط کا جواب لکھنا اسی طرح ضروری خیال کرتے جس طرح سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کے اندر تواضع و انکساری بھی انتہا کی تھی۔ حافظ قرآن تھے، تجوید کے قواعد و ضوابط سے پوری طرح بہرہ ور ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ ’’تجوید کے فنی مباحث تو میرے معیار تلاوت سے بلند ہوتے ہیں۔ ان سے استفادہ کا تو میں اہل ہی نہیں ہوں‘‘۔ یہ جملہ انتہائے انکسار کا غماز ہے۔ کیونکہ قراء حضرات کے تذکروں کا دلچسپی سے پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علم تجوید و قراء ت کے خوب خوب شناور تھے اور محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ کا آپ کو سو میں سے ایک سو پانچ نمبر دینا ہمارے دعوے کی دلیل کے لیے بذات خود بڑی دلیل ہی نہیں بلکہ بڑی تائید ہے۔
ڈاکٹر صاحب فقہی معاملات میں فروعی اختلافات کی خلیج کو پاٹنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے اپنے دور میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بڑے مفید اور اہم سیمینارز منعقد کرائے۔ بہت سے مضامین اور کتابچے بھی لکھے۔ اس حوالے سے آپ نے کاسموپولیٹن فقہ کا نیا نظریہ دیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ دنیا کے بدلتے حالات کے تناظر میں ایک نئی فقہ مدون کی جائے جو دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی میراث ہو، جس پر پوری دنیا میں عمل بھی ممکن ہو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جدید حالات میں پوری دنیا سمٹ کر ایک ملک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کا باہم رابطہ انتہائی آسان بھی ہے اور انتہائی سریع بھی ہو چکا ہے۔ فاصلہ اور وقت سب کے سب سمٹ چکے ہیں۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر علاقے کے بسنے والے مسلمان معروضی حالات کے تحت اپنے مسائل کا جائزہ لیں اور بین الاقوامی سطح پر ان کے نتائج پر غور کریں اور اس غور کے نتیجے میں درپیش مسائل کا حل تلاش کریں اور چاروں مکاتب فکر کی بنیادوں کو قائم رکھتے ہوئے ایک نئی فقہ مدون کی جائے جس پر سب کا اتفاق و اتحاد ہو۔ اس کے لیے انہوں نے عملی خاکہ بھی دیا تھا کہ ہر ملک کے علماء کا ایک بورڈ قائم کیا جائے جو اپنے ملک کے معروضی حالات کی روشنی میں پیدا ہونے والے جدید مسائل کا حل کتاب و سنت اور کتب فقہ کی مدد سے تلاش کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں تجاویز مرتب کریں۔ اس طرح مسلمانوں کے ستاون اسلامی ممالک کے چوٹی کے اہل علم حضرات کا مرکزی بورڈ عالمی اسلامی سطح پر قائم کیا جائے۔ تمام ممالک سے موصولہ نتائج و تجاویز اس بورڈ کے سامنے پیش کی جائیں اور ان کے فیصلوں کو قبول کر لیا جائے۔ اس طرح جدید مسائل کا حل جدید حالات کے تناظر میں تلاش کیا جاسکے گا اور دنیا کے سامنے اسلام کا رخ روشن واضح کرنے میں مدد ملے گی۔ فقہی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے مضامین نہایت اہم ہیں جن سے مدد لے کر جدید مسائل کو متفقہ طور پر حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کاش اہل دانش و بینش اور علماء حضرات اس اہمیت سے واقف ہوں اور فکر کی نئی راہیں تلاش کر سکیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب ’’محاضرات فقہ‘‘ سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔
سیاست کاروں کی سوچ مفادات کی اسیر ہوتی ہے ۔ مفادات بھی قومی نہیں، ذاتی۔ سیاست کار جم غفیر کا رخ دیکھ کر قبلہ متعین کرتے ہیں اور اس پیمانے کے مدنظر رخ تبدیل کرنے میں قطعاً دیر نہیں لگاتے۔ یہی پاکستان کا المیہ ہے اور اسی رویے کو عام اصطلاح میں لوٹا کریسی بھی کہا جاتا ہے۔ سیاست کار کچھ بھی کہیں ، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے جو مساعی پاکستان کے فوجی حکمران جنرل محمد ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے سرانجام دیں، وہ کسی اور کا حصہ نہ بن سکیں۔ انہوں نے پاکستان میں غیر سودی معیشت کو رائج کرنے میں مثالی کام کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے انتہائی چیدہ اور چنیدہ اہل علم سے معاونت حاصل کی، ان میں ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب ہماری اس بات کو عقیدت پر محمول کریں ، اس لیے ہم ان کے قریبی رفیق کار ڈاکٹر انیس احمد کی گواہی ڈلوانا چاہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
’’پاکستان میں سودی بنکاری سے نجات کے لیے جن لوگوں نے کام کیا اور خصوصاً جب معاملہ سپریم کورٹ کے اپیلٹ بنچ میں گیا اور پھر سپریم کورٹ کے فل بنچ نے اس مسئلے کا جائزہ لیا تو اس میں غازی صاحب نے نمایاں کردار ادا کیا۔ فیڈرل شریعہ کورٹ میں جس طرح ڈاکٹر فدا محمد خان صاحب نے فیصلے کی تحریر میں کردار ادا کیا، ایسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس خلیل الرحمن صاحب اور ڈاکٹر غازی کا اہم کردار رہا۔ ۸۰ کے عشرے میں جنوبی افریقہ میں قادیانیوں کے حوالے سے عدالتی کاروائی میں پاکستان کے جن اصحابِ علم نے عدالتِ عالیہ کو اس مسئلے پر رہنمائی فراہم کی، ان میں مولانا ظفر احمد انصاری، پروفیسر خورشید احمد صاحب ، جسٹس افضل چیمہ صاحب مرحوم اور ڈاکٹر غازی کے نام قابلِ ذکر ہیں‘‘۔
ڈاکٹر صاحب کو فرنچ زبان پر بھی دسترس حاصل تھی۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحومؒ نے سیرت الرسول کے موضوع پر ایک کتاب فرانسیسی زبان میں لکھی تھی جس کا انگریزی ترجمہ ایک ترک سکالر نے The Life and Time of Muhammad کے نام سے کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ دیکھا تو انہیں اس میں کچھ اسقام نظر آئے۔ چنانچہ آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی اصل کتاب جو فرانسیسی زبان میں تھی اور انگریزی ترجمہ کا باہم موازنہ کرکے ان اسقام کو دور کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول انگریزی ترجمہ میں بہت سے مقامات ترجمہ سے رہ بھی گئے تھے۔ آپ نے ان حصوں کو پورا کیا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ انہوں نے بطل امت، محسن پاکستان شہید اسلام جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ پڑھایا۔ ہمارے نزدیک شہید ضیاء الحق کا جنازہ پڑھانا جہاں ان کے لیے سعادت تھا، وہاں ضیاء الحق کے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بھی ثابت ہوگا، کیونکہ دونوں شخصیات تقویٰ و طہارت میں اپنا منفرد مقام رکھتی تھیں۔
آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت
اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا
شاید اس شعر کے شاعر کو مرحوم ڈاکٹر غازی سے واسطہ نہیں پڑا۔ اگر اسے ڈاکٹر صاحب سے کبھی واسطہ پڑتا تو شاید وہ یہ شعر ہرگز نہ کہتا، کیونکہ ڈاکٹر غازی مرحوم حیات دنیوی کے راستوں سے محفوظ و مامون تشریف لے گئے۔ وہ اپنی متاع حیات لٹا کر نہیں، رداے حیات کو حسنات سے مالا مال کرکے دنیا سے رخصت ہوئے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی کا تعلق ایک ایسے علمی گھرانے سے تھا جس میں بڑے قد آور علما پیدا ہوئے جو علم کے ساتھ ساتھ تصوف و سلوک کے شناور بھی تھے، جن کے نزدیک محض علم کافی نہیں، تطہیر باطن اصلاً مقصد علم تھا۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی تصوف و سلوک کے مویدین میں سے تھے، لیکن اس کے لیے جہری سری اذکار کی بحث میں نہ پڑے بلکہ سبحوا بکرۃً وعشیَّا(۱۹:۱۱) پر عمل کرتے ۔ وہ اس بات پر بھی شاید یقین نہیں رکھتے تھے کہ یاد الٰہی کے لیے مالا و دانے دار تسبیح کا سہارا ہی لیا جائے اور اس مقصد کے لیے کسی کونے کھدرے یا زاویہ ہی کو تلاش کیا جائے، بلکہ اس کے برعکس وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ زندگی اپنی ذات میں تصوف و سلوک کا نام ہے اور زندگی اگر ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت الٰہی و ریاضت الٰہی کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ وہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ ان کی سوچ ان کی فکر ان کا قلم ان کی مساعی اور دنیوی دفتری مناصب کی مصروفیات سب اسی مقصد کے حصول کے لیے تھیں۔ بقول جگر
محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں
زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں
ڈاکٹر صاحب نے شاید زندگی کے ساٹھ بہاریں بھی پوری نہ کیں لیکن اس متاع قلیل اور حیاتِ مستعار کو ہمیشہ عبادت سمجھا اور ایک ایک لمحہ بے ہوش نہیں باہوش گزارا۔ قلم کاری کو بھی عبادت خیال کیا۔ وہ عالم باعمل تھے۔ ان کے نزدیک علم محض جانکاری کا نہیں بلکہ عملی استواری کا نام تھا۔ تطہیر باطن کے بغیر علم محض ایک خبر ہے۔ آج کسے خبر نہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے۔ اس جاننے کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بعض تو بانگ دہل یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں۔ یہ سب عدم تطہیر باطن کا سبب ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں:
خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں
محض کتابی علم تطہیر باطن نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کسی صاحب بصیرت کی ضرور ت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کوئی شخص مسند تدریس پر نہیں بیٹھ سکتا تھا ، خواہ اس کا علمی مرتبہ و مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو ۔ محض علمی بلندی مسند تدریس کے لیے کافی نہ ہوتی تھی۔ علمی مقام و مرتبہ عموماً خود پسندی کا مرض پیدا کرتا ہے جو زوال شخصیت کا باعث ہوتا ہے۔ تطہیر باطن کے لیے کسی صاحب نظر شخصیت کی طرف میلان طبعی ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا تو علم نہیں کہ تطہیر باطن کے لیے ڈاکٹر صاحب کی نسبت کہاں تھی، البتہ ہم نے دیکھا اور بارہا دیکھا کہ سفر وحضر میں ذکر اذکار سے آپ کی زبان تر رہتی اور قلبی اعتبار سے آپ خاشعین ﷲ کی تصور تھے۔ جو تطہیر باطن کا ثبوت ہے۔ تقریباً نصف صدی قبل ہم نے اپنی نسبت سلوک کے اعتبار سے مولانا عبدالقادر رائے پوری سے قائم کی، لیکن یہ زمانہ ذہنی بلوغت کا نہ تھا ۔ ہم حضرت رائے پوری کی مرجعیت سے متاثر ہوئے اور لوگوں کو لمبی چادر پکڑے بیعت ہوتے دیکھا۔ ہم بھی بیٹھ لیے اور بہت سے صحبتیں اٹھائیں۔ ان کے جنازہ میں شرکت کی سعادت بھی ملی ۔ ان کے بعد اپنا رشتہ سلوک مولانا محمد زکریاؒ سے استوار کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہم کٹی ہوئی ڈور تھے لیکن، خواہش پیوستگی موجود تھی۔ دل ڈاکٹر محمود احمد غازی کی طرف مائل تھا۔ میں نے جتنی مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو قریب سے دیکھا، میرا طبعی میلان حصول تطہیر باطن کے لیے ان کی طرف راغب ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے لیطمئن قلبی کی غرض سے عرض کی: ڈاکٹر صاحب! سلوک و تصوف پر بھی آپ کے قلم سے کچھ تحریریں معرض وجود میں آئیں؟ گویا ہوئے، میرے ذہن میں اس کا خاکہ ہے، مختلف پہلوؤں سے اس پر لکھنے کا ارادہ ہے، لیکن ارادہ کی تکمیل سے قبل مدعی اجل نے دستک دی اور ڈاکٹر صاحب لبیک کہہ گئے۔
ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے دور بہت دور چلے گئے، اتنا دور کہ کوئی بھی وہاں جانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ البتہ موت اس مکانی فاصلے کو سمیٹ دیتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے ، اس سے مفر نہیں ۔ اس کے لیے فرشتۂ اجل کو بھی الزام نہیں دیا جاسکتا۔ وہ مالک الملک کی طرف سے اسی کام پر متعین ہے۔ وہ اپنا فریضہ اصول و ضوابط کے مطابق سرانجام دے رہا ہے۔ شکوہ میڈیا پر قابض لوگوں سے ہے جنہیں خبر ہی نہ ہو سکی کہ دنیا سے کون رخصت ہوا۔ کتنا بڑا خلا چھوڑ گیا۔ اس کی وجہ سے علمی دنیا پر کیا قیامت ٹوٹی۔ محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پر قابض لوگ صمٌ بکمٌ عمیٌ کی زندہ تصویریں ہیں جو پاتال سے خبریں ڈھونڈ لاتے ہیں ، جو کسی بھی مغنیہ یا مغنی کی آوازوں کے سر تال تو سنتے ہیں، ان کی باریکیوں پر پروگرام ترتیب دیتے ہیں، انہیں ڈھول کی تھاپ پر پاؤں کی جھنکار کا تو علم ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر محمود کی عظمتوں و رفعتوں کو ان کی آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ نہ ہی ان کے قلم سے لکھی تحریریں ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ نہ ہی انہیں اس علمی میراث کا پتہ چلتا ہے جو وہ قوم کے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انہیں وہ تاریخ بھی یاد نہیں رہتی جس تاریخ کو ان کی موت کا عظیم سانحہ بیت جاتا ہے۔
لَہُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِہَا وَلَہُمْ آذَانٌ لاَّ یَسْمَعُونَ بِہَا أُوْلَءِکَ کَالأَنْعَامِ بَلْ ہُمْ أَضَلُّ (۷:۱۷۹)
کان بہرے نہیں ہوتے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ یہ دل ہیں جو اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ جب قومی سطح پر یہ مرض شدت اختیار کر جائے تو پھر ایسی قوموں کو فکری انتشار، کج علمی اور کج عملی سے کوئی مسیحا نجات نہیں دلا سکتا۔ میڈیا والوں کے اس رویہ پر ہم پروفیسر عنایت علی کے الفاظ میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ
سانحے سے بڑا حادثہ یہ ہوا
کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر
مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی ۔ کچھ یادیں، کچھ تأثرات
مولانا مفتی محمد زاہد
(۳ اکتوبر ۲۰۱۰ء کو الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں منعقدہ تعزیتی نشست سے خطاب جسے مصنف کی نظر ثانی اور اضافوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔)
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد!
جیسا کہ برادرم عمار صاحب بتلا رہے تھے، طے شدہ پروگرام کے مطابق اس وقت ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ سے ہم سب نے مستفید ہونا تھا اور انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب ؒ کی گفتگو کے سحر میں مبتلا ہوں گے۔ تقریباً دو ہفتے پہلے جب مجھ سے عمار صاحب نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ اتوار کی صبح کو آئیں گے یا ہفتہ کی شام کو توشاید پہلے میری ترجیح یہ ہوتی کہ صبح کو وہاں سے نکلوں گا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب شام کو آجائیں گے تو میں نے بھی تقریباًذہن بنا لیا تھا کہ ہفتہ شام کو آ جاؤں گا اور ڈاکٹر صاحب سے مستفید ہونے کا موقع مل جائے گا اور اگلے دن بھی ڈاکٹر صاحب کا پورا بیان اول سے آخر تک سنیں گے ۔ انتظار میں لمحے گزر رہے تھے۔ آج اتوار کا د ن ہے۔ پچھلے اتوارکی صبح ساڑھے سات کے قریب ایک صاحب کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ جو انتظار کے لمحے چل رہے تھے، اب وہ انتظار یک دم ایک حسرت بن کر رہ گئی۔ ایسی ناگہانی خبر تھی کہ اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ دو تین حضرات نے فون پر اطلاع دی، پھر بھی اطمینان نہیں ہورہا تھا۔ خیال ہوا کہ ان کے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب سے رابطہ کر لوں، لیکن ایسی خبر تھی کہ ان سے رابطہ کرنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ خدانخواستہ اگر خبر غلط ہوئی تو! لیکن دل کڑا کر کے ان سے پوچھا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہی کہا: ’’مولانا! دعا فرمائیے، بھائی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔‘‘
جیسا کہ عمار صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمہ جہت شخصیت تھے، سب کا مشترکہ اثاثہ تھے اور ہر پہلو سے، صرف علم ہی نہیں، علم و عمل اور کردار ہر پہلو سے ایک جامع شخصیت تھے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور متنوع کمالات سے نوازا تھا۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالمِ دین، جدید وقدیم کے جامع اسلامی اسکالر، بہت اچھے مقرر، مصنف ومحقق، ماہر تعلیم، منتظم اور نہ جانے کیا کچھ تھے۔ رسمی طور پر تو عام طور پر کہہ ہی دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہوگیا ہے، لیکن غازی صاحب کی رحلت سے جوخلا پیداہوا، علمی اور دینی حلقوں کو جو نقصان پہنچا، دینی تعلیم وتحقیق کے مستقبل کے بارے میں سوچنے والوں کو جو دھچکا لگا، اسے اس طرح کے رسمی جملوں سے تعبیر کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ کہنے والے صحیح کہاہے :
وماکان قیس ھُلکہ ھلک واحد
ولکنہ بنیان قوم قد تہدّما
(قیس کا مرنا ایک آدمی کا مرنا نہیں۔ ایک پوری قوم کی عمارت منہدم ہو گئی ہے۔)
ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر شہزاد اقبال شام صاحب موجود ہیں۔ ان کو ڈاکٹرصاحب کی رفاقت کا شرف حاصل رہا ہے۔ وہ ان کی زندگی کے پرت ہمارے سامنے کھولیں گے اور ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل کے اعتبار سے کئی خوبیاں جو اب تک راز ہیں، وہ کھل کر سامنے آئیں گی۔ اسی طرح ہمارے محترم مخدوم و بزرگ جناب مولانا زاہدالراشدی صاحب موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ’’ولی را ولی می شناسد‘‘، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ’’جوہر کو جوہری ہی جانتا ہے‘‘۔ مولانا راشدی جیسے جوہری اور ولی ہمیں بتلائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کتنا قیمتی اثاثہ تھے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، اپنے چند تأثرات پیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔
اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی مفتی محمد مجاہد شہید ؒ ،وہ بھی اسی طرح دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے جیسا کہ آج یہاں آکر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر فاروق خان بھی دہشت گردی کانشانہ بن گئے اور انہیں شہید کردیا گیا ہے، إنا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مفتی محمد مجاہد ؒ کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد حضرت مولانا مفتی زین العابدین ؒ [معروف مبلغ تبلیغی جماعت و بانی دارالعلوم،فیصل آباد] تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ جن دنوں ان کی شہادت ہوئی، اس وقت وہ بیرون ملک سفر پر تھے۔ جب سفر سے واپس آئے تو گھر جانے کی بجائے سیدھا ایئرپورٹ سے جامعہ امدادیہ میں تشریف لائے اور طلبہ اوراساتذہ سے خطاب فرمایا۔ جن حضرات نے حضرت مفتی صاحبؒ کی گفتگو سنی ہے، ان کو یاد ہو گا کہ حضرت مفتی صاحب کے بیان کی تمہید بہت دلچسپ اور شاندار ہوتی تھی۔ اس میں تبلیغی رنگ بھی ہوتا تھا اور مفکرانہ بھی۔ مجھے ان کے الفاظ تو اچھی طرح یاد نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بات اس طرح شروع کی۔فرمایا:
’’اللہ جل جلالہ کو انسان سے بہت محبت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی قدر کی جائے۔ پھر جس میں جتنے کمالات ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اتنی ہی اس کی قدر کی جائے۔ جب کسی بندے کی اس طرح قدر نہیں کی جاتی جس طرح قدر کی جانی چاہیے تھی تو بعض اوقات اس نعمت کو اللہ تعالیٰ جلد واپس لے لیتے ہیں۔‘‘
میں یہ تو نہیں کہتا کہ ڈاکٹرصاحب کی قدر نہیں کی گئی۔ الحمد للہ ایک حد تک ان کی قدر کی گئی اور ان سے استفادہ کیا گیاہے، لیکن غالباً یہ کہنا صحیح ہو گا کہ ہم لوگوں نے انہیں صحیح طور پر بر وقت پہچانا نہیں تھا۔ ان کی خوبیوں کی طرف جو آج ہماری توجہ ہوئی، کہیں پہلے ہونی چاہیے تھی اور یہ شاید ہمارا عمومی المیہ ہے کہ صحیح وقت پر ہمیں بندے کی قدر نہیں ہوتی۔ آج بھی اللہ کے فضل وکرم سے بہت سے قابل قدر لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دن پہلے جب مولانا زاہد الراشدی صاحب فیصل آباد تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک تو عمر کے اس حصے میں آپ کو سفر زیادہ آرام دہ کرنا چاہیے، دوسرے ایک رفیقِ سفر بھی ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ اگر ایسا ذی استعداد نوجوان عالم جو کمپیوٹر کا استعمال بھی جانتا ہو، بالخصوص اچھی رفتار سے ٹائپ کرسکتا ہو، آپ کے ساتھ رہے۔ دورانِ سفر جب موقع ملے، آپ اسے املا کراتے رہیں اور وہ لیپ ٹاپ پر لکھتا جائے۔
مولانا چند سال پہلے بطور لطیفہ کے بتارہے تھے کہ ان کے ایک پوتے کے سامنے کچھ مہمانوں نے ذکر کیا کہ آپ کے دادا بہت بڑے اسکالر ہیں۔ اس پر اس نے (جو کہ اس وقت بہت چھوٹا ہوگا) کہا کہ بنے پھرتے ہیں بڑے صحافی، کمپیوٹر تو استعمال کرنا آتا نہیں! اب پوتا صاحب کی تازہ ترین رائے معلوم نہیں کہ کیا واقعی مولانا اسکالری کے امتحان میں پاس ہوگئے یا نہیں! پاس ہوبھی گئے ہوں تو اس عمر میں اعصاب کمپیوٹر پر کام کے کہاں متحمل ہوتے ہیں۔ بہر حال میں نے مولانا سے عرض کیا کہ اس طرح سے بہت سے لکھنے پڑھنے کے کام جو محض اسفار کی وجہ سے نہیں ہوپاتے، وہ ہوجائیں گے اور آپ کے بہت سے افادات جلد لوگوں تک پہنچنے کے قابل ہوجائیں گے۔ اگرچہ اس پر مولانا کا جواب تھا کہ بہت سے دعوت دینے والے مدارس خود مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان کی دعوت پر انکار بھی نہیں کر سکتا اور ان پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈال سکتا۔ خیر یہ تو ضمناً بات آگئی، اصل بات یہ عرض کررہا تھا کہ کسی کی خوبیوں سے صحیح وقت پر استفادے کی ہمارے ہاں روایت ہونی چاہیے۔
میری غازی صاحب سے پہلی شناسائی اس زمانے میں ہوئی جب میں ۱۹۸۵ء میں بین الأقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں زیر تعلیم تھا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی ہی کے ذیلی ادارے دعوہ اکیڈمی میں غالباً ڈائریکٹر تھے اور فیصل مسجد میں عموماً جمعہ بھی وہی پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کے علمی مقام کا بھی خاص اندازہ نہیں تھا، نہ ہی ان سے کسی طرح کے استفادے کا موقع ملا تھا۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا نجم الحسن تھانویؒ بھی دعوہ اکیڈمی میں ہوتے تھے جس کا ایک دفتر اس زمانے میں کراچی کمپنی (مرکز جی نائن) میں ہوتا تھا۔ جامعہ امدادیہ نیا نیا قائم ہوا تھا، اس کے کسی معاملے میں مشورہ کرنے کا کام ہمارے والد ماجد ؒ نے میرے ذمہ لگایا۔ انہوں نے غازی صاحب مرحوم کو بھی بلالیا۔ کیا صورت اور تقریب ہوئی، یہ تو یادنہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ غازی صاحب سے بات حضرت مولانا نجم الحسن صاحب ؒ ہی کے کمرے میں ہوئی، حالانکہ غازی منصب کے لحاظ سے مولانا سے اوپر تھے ۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ مولانا مجھے ساتھ لے کر خود ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے۔ اس وقت تو نوعمری کی وجہ سے اس طرف اتنا دھیان نہیں گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی ظاہری اعتبار سے اپنے ایک ماتحت کے ہاں حاضری اس بات کی غماز تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بزرگوں کے احترام جیسی مشرقی اور اسلامی روایات میں گندھی ہوئی تھی۔ زیر مشورہ معاملے میں ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے اپنی رائے دی، اس کی اصابت کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے مرتب اور منقح اندازِ گفتگو نے مجھے خاصا متأثر کیا۔
کسی علمی موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی مفصل گفتگو سننے کا پہلی مرتبہ اتفاق مولانا نصیب علی شاہ صاحب ؒ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی بنوں فقہی کانفرنس میں ہوا۔ ایک تو اس طرح کی دور افتادہ جگہ پر جانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا تیار ہوجانا یقیناًان کے حسن خلق کی دلیل تھا۔ اس کے علاوہ فقہ اسلامی کے موضوع پر انہوں نے جو مفصل گفتگو فرمائی، اس میں معلومات کی وسعت اور ندرت، گفتگو میں ایک خاص قسم کا بہاؤ اور تسلسل، زبان میں قدرے لکنت کے باوجود سامعین کو اپنے کنٹرول میں لے لینے والا مخصوص اندازِ گفتگو جیسی صفات متاثر کن تھیں جنہیں کوئی بھی شخص محسوس کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے مختلف سیمینارز، کانفرنسز اور میٹنگز میں زیارت اور استفادے کا موقع ملتا رہا اور وسعت مطالعہ، قابل رشک حافظہ اور یادداشت، مضبوط طرزِ استدلال، ایک موضوع پر جماؤ اور استطرادات سے گریز، موضوع کا احاطہ، گفتگو میں ربط اور انضباط اور مسحور کن طرزِ بیان جیسی بے شمار خوبیوں کا نقش ذہن پر مستحکم ہوتا رہا۔ اسے میری کمزوری سمجھ لیا جائے یا افتادِ طبع کہ ہمیشہ معروف اور بڑی شخصیات سے رابطہ کرنے میں حجاب سا محسوس ہوتا رہتاہے۔ اس کے باوجود جہاں کہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوتی، ان کی شفقتوں سے مستفید ہونے کا موقع ضرور ملتا۔
ایک مجلس میں ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بہتر یاد داشت کا راز کیا ہے؟ کیا کوئی نسخہ یا وظیفہ ایسا ہے جو اس چیز کے حصول میں معین ہو؟ تو اس پر، جہاں تک مجھے یاد پڑتاہے، فرمایا کہ مجھے کسی بزرگ نے یہ دعا بتائی تھی: أللہم إنّی أسألک علما لا یُنسی۔ غالباً ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب ایک کتاب کو شروع کرے تو اسے پورا پڑھنے کی کوشش کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی اپنی فکر اور توانائیوں کا محور بنالیتا ہے، وہ چیز اسے بآسانی یاد رہنے لگ جاتی ہے۔ ایک تاجر کو مختلف اشیا کے نرخ اور ان میں اتار چڑھاؤ اس طرح یاد ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی باریک تفصیلات اسے کیسے یاد رہ جاتی ہیں۔ قوت حافظہ اور یاد داشت کے یقیناًبہت سے اسباب بھی ہیں۔ ان میں طبی اسباب بھی ہوں گے، ہموم و افکار کی کمی بھی اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک پیدائشی اور قدرتی ملکہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے حکیمانہ نظام کے تحت تقسیم فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی علم ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اسے علم سے متعلق باتیں زیادہ یاد رہنے لگ جاتی ہیں۔ جس شخصیت میں یاد داشت کا یہ غیر معمولی وصف ہو، اس سے یہ سوال ضرور ہوتاہے کہ یاد داشت مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ امام بخاری سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا حافظے کی کوئی دوائی ہے؟ پہلے تو امام بخاری نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ اس طرح کی ظاہری دوائی واقعی انہیں معلوم نہیں ہوگی اور نہ ہی امام بخاری کا بے مثال حافظہ ایسے کسی ’نسخہ‘ کا مرہونِ منت تھا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد امام بخاری نے فرمایا : لا أعلم شیئا أنفع للحفظ من نہمۃ الرجل ومدوامۃ النظر، یعنی یاد داشت کے لیے دو کاموں سے زیادہ کوئی چیز میرے علم کے مطابق مفید نہیں ہے۔ ایک آدمی کی علم کے لیے بھوک اور اس کا شوق ولگن اور دوسرے کثرتِ مطالعہ۔ ( لامع الدراری از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ۱/۳۹)۔
ڈاکٹر صاحب پر متعدد اوقات میں جس طرح کی انتظامی ذمہ داریاں رہیں، ان کے ہوتے ہوئے عموماً آدمی مطالعہ وغیرہ سے کٹ جاتاہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں معلوم ہوتاہے کہ ان میں نہمۃ الرجل اور مداومۃ النظر والی بات آخروقت تک موجود رہی۔ اس بات کی گواہی ان کے خطابات اور گفتگو کے علاوہ انہیں قریب سے دیکھنے والے بھی دیتے تھے اور کبھی کبھار شرفِ رفاقت حاصل کرنے والے بھی ۔
مولانا قاری محمد حنیف جالندھری بتارہے تھے کہ ایک دفعہ مراکش کے سفر میں وہ ان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ کتب خانوں کا چکر لگانے نکل جاتے اور شام کو کئی کتابیں خرید کر لاتے اور فرماتے تھے کہ سفرمیں میری شاپنگ یہی ہوتی ہے۔ اس سفر سے واپسی پر بھی کتابوں کے دو بڑے صندوق ان کے ساتھ تھے۔ پھر کتابیں خریدتے ہی قیام گاہ پر آکر انہیں پڑھنا بھی شروع کردیتے تھے۔ ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ سفر کرنے والے ایک دوست سے سنی، لیکن اس وقت اسے وقتی چیز خیال کیا، ان کے انتقال کے بعد کئی لوگوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کثیر التلاوۃ تھے۔ بعض احباب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل کی تلاوت کرلیں۔علمی مصروفیات رکھنے والوں میں کثرتِ تلاوت کا ذوق خال خال ہی نظر آتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی ؒ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ صبح سیر کے دوران روزانہ سات منزلوں میں سے ایک منزل کی تلاوت فرمالیا کرتے تھے، بلکہ اس دوران پنسل اور کاغذ بھی جیب میں رکھتے تھے۔ ہوسکتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاں یہ اسی ’’تھانوی‘‘ روایت کا تسلسل ہو۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے علم میں آمد اور برکت کی ایک وجہ یہ کثرتِ تلاوت بھی ہوسکتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب کو ذوقِ مطالعہ کے علاوہ اپنے وقت کے کئی مشاہیر سے ملاقاتوں، ان کے ساتھ وقت گزارنے اور ان سے مختلف طریقوں سے استفادے کا وسیع موقع ملا تھا جس کا اظہار ان کی گفتگو سے بے ساختہ ہوجاتا تھا ۔ میرے لیے واقفیت کی کمی کی وجہ سے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ وہ کس شخصیت سے سب سے زیادہ مستفید اور متاثر ہوئے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ایسی فہرست میں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کا نام کافی اوپر ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ سیرت طیبہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیم اور اسلام کا قانون بین الممالک ڈاکٹر صاحب کے پسندیدہ موضوعات تھے ۔ ڈاکٹر حمید اللہ ؒ کے علاوہ بھی متعدد شخصیات سے انہیں قرب کے مواقع حاصل ہوئے۔ ان میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا نام بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ شام کے معروف عالم ڈاکٹر معروف الدوالیبی کے ساتھ انہیں وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ اور کئی متعدد شخصیات کا تذکرہ دورانِ گفتگو نوکِ زبان پر آجاتاتھا۔
ماضی قریب میں علمی نوعیت کے بہت سے واقعات کے وہ یا تو چشم دید گواہ اور ان میں شریک تھے یا ایک آدھ روای کے واسطے کے ساتھ اسے روایت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ بات تو مشہور ومعروف ہے کہ علامہ اقبال کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ فقہ اسلامی کی تدوینِ نو کا ایک خاص نہج پر کام ہو جو یقیناًاجتہادی نوعیت کا کام ہوتا اور یہ بات بھی معروف ہے کہ ان کی نظر علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری ؒ پر تھی اور انہوں نے اس سلسلے میں انہیں لاہور تشریف آوری کی دعوت بھی دی تھی جسے شاہ صاحب قبول نہیں فرماسکے تھے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار میں امریکا سے تشریف لائے ہوئے ایک اسکالر نے یہی بات کچھ اس انداز سے بیان کی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ شاہ صاحب ؒ کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ علماے دیوبند فقہ اسلامی پر کسی نئے انداز کے کام میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ ان کے خطاب کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے صدارتی خطاب میں اس معاملے کی وضاحت فرمائی اور ایک ایسے عالم کا حوالہ دیا جو شاہ صاحب ؒ اور علامہ اقبالؒ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں بنفس نفیس شاہ صاحب کے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر صاحب نے اس ملا قات کی سر گزشت ان سے براہِ راست سنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک واسطے کی سند متصل کے ساتھ بیان فرمایا کہ شاہ صاحبؒ کے انکار میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے یہ تاثر ابھرے کہ وہ اس طرح کے کسی منصوبے کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ علامہ اقبالؒ کی لاہور کے لیے دعوت موصول ہونے سے پہلے ڈابھیل والوں سے وعدہ کر چکے تھے۔ اب وعدے کی خلاف ورزی مناسب نہیں تھی، اگر یہ دعوت پہلے موصول ہوجاتی تو وہ اس پر ضرور غور کرتے۔
ڈاکٹر صاحب کی یہ عجیب خصوصیت تھی کہ جو بات ان سے متعدد مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا، ہر دفعہ تقریباً الفاظ ایک ہی جیسے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے باقاعدہ یہ تعبیر بناکر اسے کہیں بیٹھ کر رَٹ لیا ہو۔ یقیناًحقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن یاد داشت کی خاص نوعیت کی پختگی کا یہ اثر تھا۔ ایک دفعہ ایک نجی مجلس میں تبلیغی جماعت کے کام کے ابتدائی دور کے بارے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک مکالمہ انہوں نے سنایا جو ڈاکٹر صاحب کی دادی صاحبہ کے گھر میں تھانہ بھون میں پیش آیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے والد مرحوم کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کرتے تھے جو اس واقعے کے عینی گواہ تھے۔ بات چونکہ بہت اہم، تاریخی اور کام کی تھی اور تھی بھی سند متصل کے ساتھ، اس لیے کئی سال بعد جب فیصل آباد جامعہ امدادیہ میں ان کی تشریف آوری ہوئی تو ناشتے کے موقع پر وہی واقعہ دوبارہ سنانے کی فرمائش کی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اور اس مرتبہ کے الفاظ بھی تقریباً ایک ہی تھے۔ راقم الحروف تو دو مرتبہ سننے کے بعد بھی ہو بہو اسے نقل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کرسکتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ہر مرتبہ ایک ہی تعبیر کے ساتھ یعنی روایت باللفظ کرتے ہوئے سنا جو آج کے دور میں یقیناًعجیب بات ہے۔بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ جو بات ایک تعبیر میں کہہ دیتے تھے، وہ الفاظ ان کے ذہن پر نقش ہو جاتے تھے اور جب بھی وہ بات دوبارہ کہنا ہوتی تو تقریباً انہی لفظوں میں ادا کرتے تھے۔
اوپر مولانا محمد الیاسؒ اور مولانا تھانوی ؒ کے جس مکالمے کا ذکر ہوا، وہ بات چونکہ عام فائدے کی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بات یاد ہے، اس قدر قارئین کے سامنے عرض کردی جائے۔ اگر روایت میں مجھ سے کمی کوتاہی ہوجائے تو کوئی صاحب اس کی تصحیح فرما دیں۔
جس زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ؒ نے ایک خاص منہج سے دعوت وتبلیغ کا کام شروع کیا تو چونکہ یہ حضرات خود پسندی اور اعجاب برأیہ جیسی چیزوں سے بالکل دور ہوتے ہیں، اس لیے اپنی کار کردگی کو نمایاں کرنے، اسے ہر قیمت پر درست ثابت کرنے یا کسی بھی قسم کے اعتراض پر برافروختہ ہونے کی بجائے خود اس بارے میں متفکر رہتے ہیں کہ نہ معلوم میرا کام صحیح نہج پر ہوبھی رہاہے یا نہیں۔ اللہ کے مقبولین کے کاموں میں یہ بات قدرِ مشترک ہوتی ہے۔ بانی تبلیغی جماعت کے متعدد واقعات اور ملفوظات اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ بھی اس جذبے سے سرشار تھے۔ اسی جذبے کے تحت مولانا محمد الیاس ؒ نے اپنے وقت کے اکابر سے رابطہ رکھا۔ اسی موضوع پر تبادلہ خیال کرنے اور راہ نمائی حاصل کرنے کے لیے مولانا تھانوی ؒ کے ہاں بھی حاضری دی اور کچھ دن تھانہ بھون میں قیام فرمایا۔ غالباً قیام کے آخری دن میں ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ کی دادی مرحومہ نے، جن کی دونوں حضرات کے ساتھ رشتہ داری تھی، دونوں (مولانا محمد الیاس ؒ اور مولانا تھانویؒ ) کی دعوت کی۔ اس موقع پران حضرات کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وہ ڈاکٹر صاحب نقل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس ؒ نے عرض کیا کہ میں نے یہاں رہ کر کافی غور وتدبر بھی کیا ہے اور استخارہ بھی، مجھے تو اس کام پر شرح صدر ہے۔ اس کی وجوہات بھی انہوں نے تفصیل سے بیان فرمائیں۔ زیادہ گفتگو انہوں نے ہی فرمائی۔ مولانا تھانویؒ زیادہ تر خاموش ہی رہے، البتہ آخر میں حضرت مولانا تھانویؒ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس کام پر شرح صدر ہے تو اللہ کا نام لے کر اسے شروع کردیجیے، لیکن اس میں تین باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ شریعت میں جو چیزیں بھی مطلوب اور مستحسن ہیں، ان کے درجات ہیں۔ کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی مستحب ہے وغیرہ وغیرہ ( بلکہ ایک ہی کام کے مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف احکام ہوتے ہیں)۔ اس کام کے دوران شریعت کی اس درجہ بندی کو بطور خاص ملحوظ رکھا جائے کہ اس میں رد وبدل نہ ہو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ دین کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا ان میں دوسرے کام انجام دینے کی زیادہ صلاحیت ہے، انہیں اگر دعوت کے اس خاص انداز کے کام میں لگنے پر شرح صدر نہ ہو تو انہیں شامل کرنے کے لیے اصرار نہ کیا جائے۔ یہ میری ’یاد داشت ‘ کا کمال ہے کہ تیسری بات مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہی۔ غالباً کچھ اس طرح کی تھی کہ جس طرح کا خطابِ عام کرنا صرف اہل علم کا کام ہے، وہ غیر اہل علم سے نہ کروایا جائے۔
یہ واقعہ ایک طرف تو حضرت مولانا محمد الیاس ؒ کے اخلاص اور للہیت پر دلالت کرتا ہے کہ مولانا تھانوی ؒ کے اس مشورے کو انہوں نے اپنے کام کی مخالفت کا نام دینے کی بجائے طلب کے انداز میں اسے سنا، دوسری طرف اس سے مولانا تھانوی ؒ کی دور اندیشی اور فہم وفراست کا بھی اندازہ ہوتاہے ۔ چنانچہ مولانا محمد الیاس ؒ نے اپنے اس شرح صدر کی بنیاد پر جو کام شروع کیا، آج وہ ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کے مبارک فوائد اور ثمراتِ حسنہ کا انکار صرف وہی شخص کرسکتاہے جس نے آنکھیں بند کرنے کا ہی فیصلہ کر رکھا ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولانا تھانوی ؒ نے کام کے آغاز میں جو مشورے دیے تھے، آج پون صدی گذرنے کے بعد بھی وہ مشورے زندہ، تازہ اور حالات سے متعلقہ معلوم ہوتے ہیں۔
میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیا کہ یہ واقعہ اور مکالمہ خود انہی کی طرف سے لکھ کر شائع ہوجائے تو اچھا ہے، تاکہ یہ بات ریکارڈ کا بھی حصہ بن جائے۔ کسی حد تک اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہہ کر ہچکچاہٹ کا اظہار فرمایا کہ اس میں چونکہ بڑوں کی طرف اپنی نسبت کا اظہار بھی ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا۔
ڈاکٹر صاحب کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ جس کام میں افادیت کا کوئی پہلو ہوتا تو محض چھوٹے شخص کے ہاتھوں ہونے یا بظاہر معمولی نظر آنے کے باوجود اس کی حوصلہ افزائی اور راہ نمائی سے گریز نہیں فرماتے تھے۔جامعہ امدادیہ کے ایک فاضل نے، جو ایک دینی مدرسے میں استاذ ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ ؒ کے سیرت پر کسی پرانے مضمون کو ایڈٹ کر کے کتابچے کی شکل شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے مسودہ مجھے بھی دکھایا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ایک بظاہر چھوٹے شخص کے کام کو بھی انہوں نے کس دقیقہ رسی سے ملاحظہ کیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب کی رحلت سارے ہی دینی اور علمی حلقوں کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک پہلو ایساہے جس کی بنیاد یہ کہا جاسکتاہے کہ سب سے زیادہ نقصان دینی مدارس کا ہواہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جدید فکری اور تعلیمی رجحانات پر نظر تو معروف ہے ہی، اس حوالے سے وہ صرف صاحب مطالعہ ہی نہیں، صاحب تجربہ بھی تھے۔ انہیں زندگی میں مختلف رجحانات رکھنے والی شخصیات سے قرب اور ان سے استفادے کے مواقع نصیب ہوئے۔ انہیں بے شمار ایسے اسفار کا موقع ملا جن میں کئی مسلم اور غیر مسلم مفکرین اور قائدین سے تبادلۂ خیال اور مکالمے کا موقع ملا۔ وہ متعدد ایسے اہم مناصب پر بھی فائز رہے جو نہ صرف اختیارات کے اعتبار سے اہم ہوتے ہیں بلکہ ان کی یہ اہمیت بھی ہوتی ہے کہ ان کی بدولت بہت سی ایسی معلومات تک آدمی کی کسی رسائی ہوجاتی ہے جس کی عام حالات میں توقع کم ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انہیں جہاں دیدہ شخص کہا جاسکتاتھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دینی مدارس کے نظام اور مزاج سے نہ صرف واقف تھے بلکہ باقاعدہ اس نظام کے اندر سے گذرے ہوئے تھے اور ان کی شخصیت کی ابتدائی ساخت پرداخت میں اس نظام کا بڑا حصہ تھا۔ حقیقت میں انہیں جو نسبتیں حاصل تھیں اور ذاتی طور وہ جن اوصاف کے مالک تھے، ان کے مطابق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان کے اندر ایک صوفی اور ملا چھپا ہوا تھا یا انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اس لیے انہیں مسٹر وملا کی خصوصیات کے امتزاج کا ایک اچھا نمونہ قرار دیا جاسکتا ہے۔
خاندانی طور پر ایک طرف وہ کاندھلہ کے اس معروف علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جس نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت کو جنم دیا اور دوسری طرف سے وہ تھانہ بھون کے فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کی ابتدائی تعلیم وتربیت بھی دینی ماحول میں ہوئی۔ وہ بنیادی طور پر دینی مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ؒ جیسی شخصیات ان کے اساتذہ میں شامل تھیں۔ اس وجہ سے جب سوال آتا تھا کہ دینی مدارس کے اصل اہداف اور مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق ان کے نصاب و نظام میں کیا تبدیلی لائی جاسکتی ہے تو اس سلسلے میں کردار ادا کرسکنے والی جن گنی چنی شخصیات پر نظر جاتی تھی، ان میں ڈاکٹر صاحب سرِ فہرست تھے ۔
دینی مدارس پر خاصا وقت ایسا گزرا کہ جو شخص عصری جامعات کی لائن اختیار کرلے، اس سے گریز کی راہ اختیار کی جاتی تھی اور ایسے شخص کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا جاتا تھا، خواہ وہ ان کے اندر سے ہی نکل کر کیوں نہ گیا ہو ، تاہم پچھلے کچھ عرصے میں اس رجحان میں خاصی تبدیلی آئی ہے اور خود ڈاکٹر صاحبؒ سے بھی بعض اہل مدارس استفادے کے لیے رجوع کرنے لگے تھے۔خصوصاً ملک کے ایک اہم اور معروف ادارے جامعۃ الرشید نے، جس کے فکری پس منظر اور ’’مسٹر گریزی‘‘ کی روایت کو دیکھتے ہوئے اس پر تجدد پسندی کا الزام لگانا اتنا آسان نہیں ہے، کچھ عرصہ سے بہت اہتمام سے ڈاکٹر صاحب ؒ کو اپنے ہاں مدعو کرنے کا سلسلہ شروع کردیا تھا جو نہ صرف بذاتِ خود خوش آئند بات تھی بلکہ اس کے فوائد کے متعدی ہونے کے امکانات واضح ہورہے تھے اور یہ توقع بندھنے لگی تھی کہ دینی مدارس ڈاکٹر صاحب ؒ جیسی شخصیات، جو دونوں جہتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھتی ہیں، کی فکر اور تجربے سے استفادہ کرنے لگیں گے اور ڈاکٹر صاحب دو ایسے طبقوں کے درمیان پل کا کام دیں گے جن کے درمیان قدرِ مشترک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ اور اسلامی تعلیمات کو زندگی کے ہر شعبے میں جیتے جاگتے انداز میں دیکھنے کی تڑپ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لگتا تھا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ؒ نے دنیا میں گھوم پھر کر اور مختلف اداروں میں اور مختلف شخصیات کے ساتھ کام کرکے جو تجربہ حاصل کیا ہے، اسے دینی مدارس کے اہداف کے مطابق بنا کر اس سے استفادے کا ایک سلسلہ چل نکلے گا، اس لیے میں نے اوپر عرض کیا کہ غالباً یہ کہنا درست ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی رحلت سے سب سے زیادہ نقصان دینی مدارس کو ہوا ہے۔
چند دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحبؒ مدرسہ کی لائن کے آدمی تھے، دوسری طرف کیوں نکل گئے؟ میں نے کہا: دوسری طرف نکل گئے تو اچھا ہوا۔ ادھر سے جو کچھ لے کر آئے، اس کو ہم لے لیتے اور مدرسوں میں منتقل کر دیتے۔ ان کے علم سے استفادہ کرتے۔ اگر بچوں کا والد کہیں باہر سفر پر جائے تو بچوں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارا والد ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے گا۔ ڈاکٹر صاحبؒ اگر دوسری طرف نکلے ہیں تو ہمیں انتظار ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے لیے ڈاکٹر صاحبؒ کیا تحفہ لے کر آئیں گے۔ یقیناًدینی مدارس کو دینے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ تھا۔
دو سال پہلے جب راقم الحروف کی طالب علمانہ کاوش ’’ تکملۃ معارف السنن‘‘ کی پہلی جلد چھپ کر منظر عام آئی تو کئی احباب کا اصرار تھا کہ اس حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوجائے۔ جامعہ امدادیہ میں دورۂ حدیث شریف کے طلبہ سال کے اختتام پر ایک الوداعی تقریب منعقد کرتے ہیں، ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ تقریب اس حوالے سے ہو۔ اس مقصد کے لیے پہلے مولانا زاہد الراشدی اور بعض دیگر اہل علم سے رابطہ ہوا ، لیکن ان سے وقت کے حصول کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹرصاحب قطر سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے برادرِ مکرم مفتی محمد طیب صاحب مدظلہم کے کہنے پر ان سے گذارش کی۔ انہوں نے کمالِ شفقت فرماتے ہوئے بلا ترد د وقت عنایت فرمایا۔ احقر نے کتاب کا ایک نسخہ ملاحظہ کے لیے روانہ کیا۔ تشریف آوری کی تاریخ سے چند دن پہلے جب راقم الحروف نے فون پر حتمی انتظامات اور ترتیب کے لیے رابطہ کیا تو یہ ان کی بڑائی اور خورد نوازی تھی کہ فرمایا کہ آپ کی کتاب میں نے دیکھ لی ہے، اس نے مجھے مسخر کرلیا ہے۔ اب آپ جیسے کہیں گے، ویسے ہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے قیام کے لیے اچھے ہوٹل میں انتظام کا ارادہ کیا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحبؒ کو معلوم ہوا تو انہوں نے سختی سے منع کردیا اور فرمایا کہ میں مدرسے میں ہی ٹھہرنا پسند کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب ؒ نے علما اور طلبہ سے ان کی ذمہ داریوں کے موضوع پر بھی خطاب فرمایا اور تکملہ معارف السنن کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں تدوین حدیث اور صحاحِ ستہ کے موضوع پر بہت ہی مؤثر اور انکشافات سے پر بیان فرمایا ( جو قلم بند ہوچکاہے اور ڈاکٹر صاحب اس پر نظر ثانی اور نظر ثالث بھی فرما چکے ہیں، ان شاء اللہ جلد شائع کرنے کا ارادہ ہے۔) حقیقت یہ ہے کہ متعدد حضرات کو حدیث شریف کے حوالے سے منعقد ہونے والی ایک مجلس میں یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو مدعو کرنا ہوسکتا ہے کہ عجیب سا معلوم ہوا ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب ؒ کا خطاب خود ہی ایسے اشکالات کا جواب تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حدیث کے استناد پر جو یقین اب حاصل ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، فجزاہ اللہ عنا خیر الجزاء وأحسنہ۔
ڈاکٹر صاحب کے خاندان اور ابتدائی تعلیمی پس منظر کو دیکھا جائے تو ایک خاص حلقۂ فکر سے ان کا تعلق نظر آتاہے جو بر صغیر میں اپنی گہری جڑیں رکھتاہے۔ ایک حد تک یہ فطری سی بات ہے کہ آدمی کے لیے اپنی جڑوں سے الگ ہونا انتہائی مشکل ہوتاہے۔ ڈاکٹر صاحب کے فکر و عمل پر یقیناًیہ پس منظری اثرات ضرور ہوں گے، لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود کو ہر قسم کے تعصبات سے پاک رکھا، بلکہ غالباً یہ کہنا درست ہوگا کہ انہوں نے خود کو کسی خاص حلقۂ فکر کی طرف منسوب کرنے یا اس کا ترجمان باور کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کی شناخت دینی علوم کے ایک ایسے شناور کی تھی جسے مسلمانوں کے تمام طبقات اپنا اثاثہ سمجھتے تھے۔ ان کا اگر کوئی ’’ تعصب‘‘ تھا تو صرف امت مسلمہ کا درد اور اس کا عمومی مفاد تھا، اس حوالے سے وہ مغرب شناس ضرور تھے، اس سے مرعوب یا اس کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہرگز نہیں تھے۔
میں نے ڈاکٹر صاحب ؒ کا گھر سب سے پہلے اس وقت دیکھا جب جنازے کے لیے حاضری ہوئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جنازے کو اٹھا کر باہر لایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جیسی معروف شخصیت جو اہم مناصب پر فائز رہی ہو، ایک ایسے حاکم کے زمانے میں وزیر اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے رکن رہے جس کی طاقت کا سورج اس وقت سوا نیزے پر تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ان کا خاصا بڑا مکان ہوگا، لیکن سرسری طور پر باہر ہی سے ان کا مکان دیکھنے کا اتفاق ہوا جو میرے لیے ان کے مقام کے لحاظ سے حیرت کا باعث بھی تھا اور ان کی درویشی کی دلیل بھی۔
بہر حال موت سے کسی کو مفر نہیں۔ جو اس دنیا میں آیا ہے، اسے یہاں سے جانا بھی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کی حکمت بالغہ کے تحت ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن مفارقت اور جدائی کا غم فطری امر ہے۔ اس حادثے پر نہ معلوم کتنے لوگ خود کو تعزیت کا مستحق سمجھتے ہوں گے۔ سب کی خدمت میں تعزیت پیش ہے، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ؒ کے اہل خانہ، ان کی والدہ ماجدہ، ان کے برادر مکرم جناب ڈاکٹر احمد الغزالی، ان کی اولاد اور ان کے برادرِ نسبتی جناب ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ چند خوشگوار یادیں
محمد مشتاق احمد
(رمضان کے بعد سے میں مسلسل بیمار رہا ہوں ۔ پہلے بخار ، پھر ملیریا ، پھر ٹائیفائیڈ اور پھر بیماریوں کے aftershocks ۔ تاہم برادرد محترم جناب عمار خان ناصر نے جب ذکر کیا کہ وہ استاد محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ’’الشریعہ ‘‘کی خصوصی اشاعت کا اہتمام کررہے ہیں تو دل سے بے اختیار ان کے لیے دعا نکلی ۔ میرا ارادہ تو اصل میں یہ تھا کہ غازی صاحب کی بعض تحریرات اور ان کے پیش کردہ بعض تصورات پر تفصیلی مقالہ لکھوں لیکن کچھ تو بیماری کی وجہ سے اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ مقالہ ابھی ادھورا ہی ہے ۔ تاہم غازی صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے چند لمحات کا تذکرہ ’’الشریعہ‘‘ کے لیے پیش کرنے کی جسارت کررہا ہوں۔)
۲۶ ستمبر ۲۰۱۰ء کی صبح ڈاکٹر محمد منیر صاحب، سربراہ شعبۂ قانون، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد نے اطلاع دی کہ استاد محترم جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب حرکت قلب بند ہوجانے کی وجہ سے انتقال کرگئے ہیں۔ کافی دیر تک صدمے کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ آنسوؤں اور دعاؤں کا ایک عجیب امتزاج تھا جو والدہ مرحومہ کی وفات کے بعد پہلی دفعہ اتنی شدت سے محسوس کیا۔ بے بسی کے احساس نے صدمے میں اور بھی اضافہ کیا کیونکہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرنے مجھے سفر سے منع کیا تھا۔ البتہ ایک بات نے بہت حوصلہ دیا کہ غازی صاحب کے شاگردوں نے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہایت شدت سے کیاْ۔ بے شمار لوگوں نے فون یا ایس ایم ایس کیے یا ای میل کیے۔ غازی صاحب کے شاگرد ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہے ، اور پھر ایک دوسرے سے چھپ کر تنہائی میں روتے رہے۔ ان گفتگوؤں میں ہم نے غازی صاحب کے ساتھ گزرے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیے۔ آج ایسے ہی چند لمحات ’’ الشریعہ‘‘ کے قارئین کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں ۔
ابتدائی دور
راقم الحروف نے ۱۹۹۴ء میں ایف ایس سی کے بعد بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی یونیورسٹی کی ’’بین الاقوامی‘‘ اور ’’اسلامی‘‘ دونوں خصوصیات بہت نمایاں تھیں۔ طلبا میں اکثریت غیر ملکیوں کی تھی۔ ساٹھ فی صد نشستیں غیر ملکی طلبا کے لیے اور چالیس فی صد نشستیں پاکستانی طلبا کے لیے مخصوص ہوتی تھیں، چنانچہ پچاس سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبا اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ فیصل مسجد کے قریب واقع کویت ہاسٹل تو امت مسلمہ کی کثرت میں وحدت کی زبردست مثال تھا۔ یونیورسٹی کی عمومی فضا پر اسلامیت کے ساتھ ساتھ عربیت کا پہلو بھی غالب تھا۔ کلیہ عربی، کلیہ اصول الدین اور کلیہ شریعہ کے طلبا کے لیے تو ویسے بھی عربی میں مہارت ضروری تھی، لیکن نہایت خوش آئند بات یہ تھی کہ اکنامکس اور کمپیوٹر کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے طلبا بھی عربی سے مناسبت رکھتے تھے۔
یونیورسٹی میں ہر ہفتے مختلف شعبوں کی جانب سے متنوع موضوعات پر سیمینار ہوتے تھے۔ میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ دو گھنٹے کے اس طرح کے سیمینار زمیں بیٹھ کر جو کچھ میں نے سیکھا، وہ شاید چھ گھنٹے کی کلاسز میں نہیں سیکھ پاتا۔ علمی اور ادبی پہلو سے تویہ سمینارز نہایت مفید ہوتے ہی تھے، لیکن دیگر کئی پہلوؤں سے بھی ان سیمینارز کا بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح کے ایک سیمینار میں ہمارے ایک کلاس فیلو اسٹیج سیکریٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انھوں نے صدر جامعہ کو خطاب کے لیے بلایا تو پورا نام لینے کے بجائے محض ’’ڈاکٹر شافعی‘‘ کہہ کر انھیں خطاب کی دعوت دی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسٹیج پر بیٹھے ڈاکٹر غازی صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر جب غازی صاحب خطاب کے لیے اٹھے تو انھوں نے اسٹیج سیکریٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں جنھیں ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ چونکہ آپ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ کسی بھی مقرر کو دعوت دینے سے پہلے ان کا پورا نام لیا کریں اور ادارے کے ساتھ ان کا تعلق مناسب الفاظ میں بیان کیا کریں۔ چنانچہ غازی صاحب کی تجویز یہ تھی کہ ’’ڈاکٹر شافعی‘‘ کہنے کے بجائے آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا: ’’جناب ڈاکٹر حسن محمود عبد اللطیف الشافعی، صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد‘‘۔ غازی صاحب کی یہ بات ہم سب نے یاد رکھی اور آج بھی جب میں اپنے طلبا میں کسی کو پہلی دفعہ اسٹیج سیکریٹری کے فرائض انجام دینے کے لیے کہتا ہوں تو دیگر نصیحتوں کے ساتھ یہ نصیحت بھی لازماً کرتا ہوں۔
اس طرح کے سیمینارز میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی مقرر نے انگریزی میں تقریر کی اور مہمانوں میں بعض ایسے تھے جو انگریزی نہیں سمجھتے تھے یا اس کے برعکس ہوا کہ تقریر عربی میں کی گئی لیکن بعض مہمان عربی نہیں سمجھتے تھے تو اس وقت کے صدر جامعہ جناب ڈاکٹر حسین حامد حسان فوراً ڈاکٹر غازی صاحب سے درخواست کرتے کہ وہ اس تقریر کا خلاصہ انگریزی یا عربی میں پیش کریں اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ غازی صاحب نے ہچکچاہٹ محسوس کی ہو۔ وہ اٹھتے اور جب خلاصہ ہیش کرتے تو سامعین نہ صرف ان کی زبان دانی کی وجہ سے، بلکہ ان کی قوت حافظہ کی بنا پر بھی انگشت بدنداں رہ جاتے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب ایک نہایت اہم موضوع پر اپنے فاضلانہ خیالات کا اظہار کررہے تھے کہ اچانک ہی (out of the blue) صدر جامعہ نے غازی صاحب سے کہا کہ وہ ساتھ ساتھ اس کا عربی ترجمہ بھی کرتے جائیں۔ ہم میں سے کئی طلبا کی رائے یہ تھی کہ غازی صاحب جیسے بڑے عالم کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور ان کی قدر ناشناسی ہے کہ ان کو اس طرح کے کام کا کہا جاتا ہے اور وہ بھی یوں اچانک، لیکن غازی صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اٹھے اور انگریزی سے عربی میں فی البدیہہ ترجمہ شروع کردیا۔ گیلانی صاحب دو دو تین تین جملے بولتے اور غازی صاحب فی البدیہہ ان کا نہایت فصیح و بلیغ ترجمہ کرتے جاتے۔
انگریزی اور عربی کے علاوہ کئی دیگر زبانوں، بالخصوص فارسی اور فرانسیسی میں بھی ان کی مہارت کا یہی عالم تھا۔ اقبال کا سارا کلام اور بالخصوص فارسی کلام ان کو ازبر تھا۔ انھوں نے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرانسیسی زبان سے انگریزی میں ترجمہ کی جس کی پہلی جلد ادارۂ تحقیقات اسلامی نے شائع کی۔ ہمارے بعض دوست کہا کرتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں مہارت غازی صاحب کا خاندانی ورثہ ہے، کیونکہ ان کے بھائی محترم جناب ڈاکٹر محمد الغزالی بھی اس معاملے میں اگر ان سے آگے نہیں تو پیچھے بھی نہیں ہیں۔
ایک دفعہ غازی صاحب نے مجھے پشتو زبان کی بعض ایسی خصوصیات کی طرف توجہ دلائی جس کی طرف میرا کبھی دھیان نہیں گیا تھا، باوجود اس کے کہ پشتو میری مادری زبان ہے اور پشتو شعر و ادب سے مجھے تھوڑا بہت شغف بھی ہے۔ غیر ملکی وفود کے ساتھ ملاقات سے پہلے غازی صاحب کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کی زبان کے چند مناسب کلمات اور جملے، بالخصوص خیر مقدمی کلمات سیکھ لیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا بھی کریں۔ چنانچہ بعض اوقات وہ اس ملک کے کسی طالب علم کو بلا کر اس سے مدد بھی لیتے تھے۔ پھر جب وہ غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ پہلی ملاقات میں انہی کی زبان اور انہی کے لہجے میں خیر مقدمی کلمات کہتے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔
اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ محبت
اقبال کے ساتھ غازی صاحب کو والہانہ محبت تھی اور مختلف مواقع پر وہ اس محبت کا اظہار بھی نہایت پر اثر انداز میں کرتے تھے۔ کلام اقبال کا جس طرح بر محل استعمال وہ کرتے تھے، وہ بھی بس انہی کا خاصہ تھا۔ اقبال کے ساتھ محبت کی وجہ سے غازی صاحب کو ان سے بھی محبت تھی جن سے اقبال کو محبت تھی۔ چنانچہ جب غازی صاحب کو معلوم ہوا کہ میرے والد صاحب نے ایم فل اقبالیات کے مقالے میں ’’اقبال اور افغانستان‘‘ کے موضوع پر تحقیق کی ہے اور وہ تحقیق کتابی شکل میں شائع بھی ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے تو اقبال سے بھی محبت ہے اور افغانستان سے بھی، اس لیے پہلی فرصت میں یہ کتاب لے آئیے گا۔ اس کے بعد جب بھی غازی صاحب سے ملاقات ہوئی وہ والد صاحب کا نہایت محبت سے ذکر کرتے تھے اور ان کی صحت کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔
اقبال کے ساتھ غازی صاحب کی والہانہ محبت کا اندازہ مجھے اپنے زمانۂ طالب علمی میں ان علمی و ادبی مجالس میں ہوا جن کا انعقاد کلیہ عربی کے پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب نومبر کے مہینے میں کرتے تھے۔ ان مجالس میں اہل علم، بالعموم عربی زبان میں، اقبال اور کلام اقبال پر علمی مقالات پیش کرتے۔ ان مجالس میں ایک خاصے کی چیز یہ ہوتی تھی کہ مجلس کے آخر میں کلیہ عربی کے عمید جناب ڈاکٹر رجاء جبر اقبال کے فارسی کلام میں کسی حصے کا انتخاب کرکے اس پر اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں تفصیلی درس دیتے۔ غازی صاحب ان مجالس کے روح رواں ہوتے تھے۔ وہ نہ صرف خود فکر اقبال کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے بلکہ دوسرے اہل علم کے مقالات پر بعض اوقات تعلیقات بھی پیش فرماتے۔ ایک دفعہ اس طرح کی ایک مجلس میں ایک عرب مقرر نے شگفتہ اردو زبان میں اقبال کے انقلابی فکر پر ایک دلچسپ مقالہ پیش کیا۔ اس مقالے میں کسی وجہ سے زیادہ تر اقبال کے ان اشعار کا انتخاب کیا گیا تھا جن میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا یا ’’رسم شبیری‘‘ ادا کرنے کی ترغیب تھی ۔ اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا تھا کہ اقبال شاید تشیع کی طرف مائل تھے۔ مقالے کے اختتام پر غازی صاحب اسٹیج پر تشریف لائے اور ’’تعلیق ‘‘ کی صورت میں اس تاثر کی نفی کی اور ایک متوازن رائے قائم کرنے کے لیے اقبال کے دیگر اشعار اور اقوال کا حوالہ دیا۔
اقبال کی طرح غازی صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی عقیدت اور محبت تھی اور اپنی تقاریر میں وہ قائد اعظم کے اقوال کے بر محل حوالے بھی دیا کرتے تھے۔ ۲۰۰۳ء کی بات ہے کہ اسلام آباد میں مولانا نصیب علی شاہ ہاشمی ؒ کی کاوشوں سے ایک عظیم الشان فقہی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس سے جناب غازی صاحب نے بھی خصوصی خطاب کیا اور اس وقت مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور غازی صاحب کی جرأت رندانہ پر رشک بھی آیا جب انھوں نے علمائے کرام کی اس مجلس میں اسلامی معاشی نظام پر گفتگو کا آغاز کلام اقبال اور اقوال قائد سے کیا۔ انھوں نے اقبال کے خطبۂ الٰہ آباد کا حوالہ دیا جس میں اقبال مسلمانوں کے الگ قومی تشخص کی بات کرنے کے علاوہ مسلمانوں کے معاشی مسائل کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے قائد اعظم کے ساتھ اقبال کی خط و کتابت کا ذکر کیا جس میں اقبال نے قائد اعظم کو مسلمانانِ برصغیر کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے قائل کیا۔ مجھے غازی صاحب کی یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے منزل کا تعین کیا بلکہ اس منزل تک پہنچانے کے لیے رہبر کا بھی انتخاب کیا۔ غازی صاحب نے اس خط و کتابت کے حوالے سے مزید کہا کہ اقبال نے اس اہم بات کی طرف بھی قائد اعظم کی توجہ دلائی کہ ہندو ساہوکار مسلمانوں کا معاشی استحصال کررہے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کی آزادی کا خواب تبھی شرمندۂ تعبیر ہوسکے گا جب ان کی معیشت ان ساہوکاروں کے قبضے سے آزاد کرائی جائے۔ اس کے بعد غازی صاحب نے قائد اعظم کی اس تقریر کا حوالہ دیا جو انھوں نے اپنی وفات سے صرف دو ماہ اقبل سٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر کی اور جس میں آپ نے فرمایا کہ مغربی معاشی نظام نہ صرف یہ کہ انسانوں کے مسائل کے حل میں ناکام رہا ہے بلکہ اس کی وجہ سے دو بڑی جنگیں بھی لڑی گئیں اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام تشکیل دے جو اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہو کیونکہ صرف اسلامی نظام ہی معاشی عدل کو یقینی بنا سکتا ہے اور انسانوں کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے ۔
قانون کی پابندی
غازی صاحب کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے قول و فعل سے قانون کی پابندی اور احترام کا درس دیتے تھے۔ میں یہاں دو ایسے واقعات کا حوالہ دوں گا جن کا میں خود شاہد ہوں۔
یہ دسمبر ۱۹۹۸ء کی بات ہے کہ میں اپنے تعلیمی کیرئیر کے ایک نہایت اہم موڑ پر پہنچ کر اچانک ہی ایک مسئلے کا شکار ہوگیا۔ اسلامی یونیورسٹی میں بی اے ۔ ایل ایل بی ( آنرز ) شریعہ و قانون کے پروگرام کا دورانیہ دس سمسٹرز (پانچ سال ) پر مبنی تھا۔ اس لحاظ سے میرے کورس کا اختتام جون ۱۹۹۹ء میں ہونا تھا، لیکن میں نے تین سال گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران میں اضافی کورسز پڑھے اور یوں یہ امکان پیدا ہوا کہ میرا کورس وقت سے پہلے دسمبر ۱۹۹۸ء میں ہی پورا ہوجائے۔ نیز اس وقت تک میں مسلسل آٹھ سمسٹرز میں اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا رہا تھا۔ گویا اس نویں سمسٹر میں اگر میں یہی پوزیشن برقرار رکھتا تو بی اے اور ایل ایل بی دونوں میں گولڈ میڈل بھی حاصل کرلیتا، مگر میری والدہ مرحومہ، جو کینسر کی مریضہ تھیں، کی بیماری کی وجہ سے میں کئی کلاسز نہیں لے سکا۔ قانون یہ تھا کہ طالب علم کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت تبھی دی جاتی جب وہ کم از کم ۸۰ فی صد تک کلاسز میں حاضرہوا ہو۔ متعلقہ کورس کے استاد کو حق تھا کہ وہ مناسب عذر کی بنا پر طالب علم کو ۵ فی صد تک رخصت دے اور کلیہ کے عمید کو مزید ۵ فی صد تک تخفیف کا اختیار تھا۔ چھ کورسز میں میری حاضری پوری تھی، لیکن دو کورسز میں میری حاضری ۷۰ فی صد سے کم تھی، چنانچہ مجھے دو کورسز کے امتحان میں بیٹھنے سے روکا گیا ۔
غازی صاحب اس وقت وائس پریزیڈنٹ (اکیڈمکس) تھے۔ چنانچہ میں نے ان کو درخواست لکھی کہ وہ میرے سابقہ تعلیمی ریکارڈ اور میری موجودہ مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ جس وقت میں ان کے آفس میں داخل ہورہا تھا، وہ (غالباً سپریم کورٹ میں کسی مقدمے کی سماعت کے لیے) نکل رہے تھے۔ انھوں نے کھڑے کھڑے میری بات سنی۔ پھر کہا کہ قانون کے تحت تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے انھیں تفصیل سے اپنے سابقہ ریکارڈ سے آگاہ کیا، لیکن ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ انھوں نے کہا سابقہ ریکارڈ کی وجہ سے قانون سے انحراف کی گنجائش تو نہیں نکلتی۔ نوجوانی کا دور تھا اور خون بھی گرم تھا۔ میں نے انتہائی تیز لہجے میں کہا کہ ساڑھے چار سال تک میں نے جو محنت کی ہے، کیا آپ اسے ایک ہی ٹھوکر میں ھباء منثورا کردینا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر غازی صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور انھوں نے میرے شانے پر تھپکی دے کر کہا کہ میں دو گھنٹے بعد آفس آؤں گا اور دیکھوں گا کہ تمھارے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں۔ بعد میں جب وہ آئے اور میرے ایک نہایت ہی محترم استاد نے ان سے اس سلسلے میں بات کی تو غازی صاحب نے انھیں بتایا کہ اس نوجوان سے ہمدردی کے باوجود میں اس کے لیے کچھ نہیں کرسکتا، کیونکہ پورے کیس کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قانون کے تحت تخفیف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گولڈ میڈل سے محرومی کے باوجود غازی صاحب سے میری محبت میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ۔ان کی وہ مسکراہٹ اور تسلی دینے کا ان کا وہ انداز مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے اور اب بھی میں اسے اپنے لیے ان کی جانب سے ایک انعام سمجھتا ہوں۔
ایک اور واقعہ یاد آرہا ہے۔ ۲۰۰۶ء میں جب وہ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے عہدے سے فارغ ہوئے تو انھوں نے پھر کلیہ شریعہ میں پروفیسر شریعہ کے طور پر پڑھانا شروع کیا۔ ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب اس وقت کلیہ کے عمید تھے۔ انھوں نے مختلف موضوعات پر اساتذہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے تحقیقی خاکوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ یونیورسٹی کے ریسرچ فنڈ سے اساتذہ کی مدد کی جائے۔ فاروقی صاحب نے غازی صاحب کو اس کمیٹی کا چیئر مین بنایا اور دیگر سینئر اساتذہ کے ساتھ وہ خود اس کے ممبر بنے، جبکہ مجھے انھوں نے اس کمیٹی کا سیکریٹری بنا دیا ۔ جب میں اس کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے غازی صاحب سے ملا تو انھوں نے کہا کہ قانون کے تحت اس طرح کی کسی بھی کمیٹی کا سربراہ عمید کلیہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات فاروقی صاحب کو بتائی تو انھوں نے کہا کہ غازی صاحب کی موجودگی میں کوئی اور کیسے اس کمیٹی کا سربراہ ہوسکتا ہے؟ اب جب میں نے غازی صاحب کو یہ بات بتائی تو میں نے صاف محسوس کیا کہ یہ بات انھیں ناگوار گزری ہے۔ انھوں نے فوراً یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کا مجموعہ اٹھا کر اس میں متعلقہ ضابطہ مجھے دکھادیا اور پھر پوچھا کہ اس ضابطے کی موجودگی میں عمید کے سوا کوئی اور اس کمیٹی کا سربراہ نہیں ہوسکتا۔ پھر انھوں نے یہی بات متعلقہ ضابطے کے حوالے سمیت لکھ کر مجھے دے دی کہ یہ نوٹ فاروقی صاحب کو دکھائیں۔ یوں غازی صاحب کے احترام کے باوجود فاروقی صاحب مجبوراً کمیٹی کے سربراہ بنے۔
کلیۃ الشریعۃ و القانون کے ساتھ خصوصی محبت
غازی صاحب نے اسلامی یونیورسٹی میں کئی کلیدی عہدوں پر کام کیا۔ وہ دعوہ اکیڈمی اور شریعہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے اور یونیورسٹی کے نائب صدر برائے اکیڈمکس (تعلیمی امور) کے طور پر بھی انھوں نے کافی عرصہ کام کیا۔ ۲۰۰۴ء سے ۲۰۰۶ء تک یونیورسٹی کے صدر کے طور پر انھوں نے خدمات انجام دیں اور ۱۹۸۵ء کے بعد سے جب یونیورسٹی ’’بین الاقوامی ‘‘ بنی تھی، وہ پہلے پاکستانی تھے جو صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس تمام عرصے میں غازی صاحب نے کلیۃ الشریعۃ و القانون کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق برقرار رکھا۔ چنانچہ وہ صدر کے طور پر کام کرنے کے دوران میں اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اس کلیہ میں کلاسز پڑھاتے رہے۔ انھوں نے یونیورسٹی کے ریکٹر جناب جسٹس (ریٹائرڈ ) خلیل الرحمن خاں کو قائل کیا کہ وہ قانون کے طلبا کو پاکستان کے دستوری قوانین پر خصوصی لیکچر دیں۔ صدارت کی مدت پوری ہونے کے بعد غازی صاحب نے کلیۃ الشریعۃ و القانون میں پروفیسر شریعہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں اور خواتین اور مردوں کے دونوں کیمپسز میں پی ایچ ڈی اور ایل ایل ایم کے علاوہ ایل ایل کی جونیئر کلاسز کے ساتھ بھی کورسز لیے۔
۲۰۰۴ء سے ۲۰۰۶ء تک کا دور، جبکہ غازی صاحب صدرجامعہ تھے، کلیۃ الشریعۃ کے لیے بڑا مفید رہا ۔ صدر جامعہ کے طور پر غازی صاحب تھے اور ریکٹر کے طور پر جسٹس خلیل الرحمان تھے جو ویسے بھی شعبۂ قانون سے متعلق تھے اور پروفیسر محمد منیر صاحب کلیۃ الشریعۃ کے نائب عمید تھے جو نہایت ہی سرگرمی سے کلیۃ الشریعۃ کی ترقی اور بہتری کے لیے کوشاں تھے۔ چنانچہ اسی دور میں ایک طرف کلیۃ الشریعۃ کے طلبا کے لیے خصوصی کمپیوٹر لائبریری بنائی گئی تو دوسری طرف شعبۂ قانون نے ایل ایل ایم میں تین تخصصات، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ٹریڈ لا اور کارپوریٹ لا میں ڈگری پروگرام شروع کیے۔ غازی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ کلیۃ الشریعۃ و القانون نہ صرف اسلامی یونیورسٹی کی مادر کلیہ ہے (کیونکہ یونیورسٹی کا آغاز ہی کلیۃ الشریعۃ سے ہوا تھا) بلکہ یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد کے حصول میں اب بھی یہ کلیہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے ۔
دیانت
جناب غازی صاحب کی شخصیت اور کردار کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ بالخصوص مالی امور میں حد درجے کی دیانت داری کے حامل تھے۔ استاد محترم جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ غازی صاحب کو یونیورسٹی کے قواعد کے تحت یہ اجازت تھی کہ وہ گھر پر سرکاری ٹیلی فون کی سہولت لیں، لیکن انھوں نے کبھی بھی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ اس ٹیلی فون کا استعمال صرف سرکاری کاموں ہی کے لیے ہوگا۔ ڈاکٹر انصاری سے ہی سنا کہ جب غازی صاحب کا بطور صدر جامعہ دفتر میں آخری دن تھا اور دفتر سے اپنی کتابیں وغیرہ جمع کرنے میں انھیں بہت دیر ہوئی تو انھوں نے اپنے بھائی جناب غزالی صاحب کو رات گئے تک روکے رکھا کہ فارغ ہونے کے بعد وہ ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں گھر جائیں گے، کیونکہ عہدے سے فراغت کے بعد وہ یہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ سرکاری گاڑی میں گھر جائیں۔
اس دیانت داری کا ایک مظہر یہ تھا کہ وہ انتہائی حد تک وقت کی پابندی کرتے تھے۔ ہم اکثر حیران رہتے تھے کہ جس طرح کی مصروفیات ان کی ہیں ان میں وہ اتنے بڑے علمی و تحقیقی کاموں کے لیے وقت کیسے نکال پاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ان کی زبانی ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا ایک واقعہ سنا تو یہ حیرت کافی حد تک دور ہوگئی۔ غازی صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ کسی یورپی ملک میں ایک سیمینار میں وہ ڈاکٹر حمید اللہ کے ساتھ شریک تھے تو سارا دن کافی مصروف رہا اور شام کو غازی صاحب کو موقع ملا کہ وہ اپنی ایک زیر تصنیف کتاب کا مسودہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو دکھا سکیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر غازی صاحب کو اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ غازی صاحب کہتے ہیں کہ اگلی صبح ڈاکٹر حمید اللہ نے انھیں وہ مسودہ دے دیا تو ان کا پہلا تاثر یہ تھا کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات انھیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کئی سو صفحات کے اس مسودے پر تقریباً ہر دوسرے تیسرے صفحے پر ڈاکٹر حمید اللہ نے کوئی تبصرہ، کوئی نوٹ، کوئی مشورہ لکھا تھا۔ غازی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد کوئی اتنا کام کیسے کرسکتا ہے جبکہ اگلے دن پھر اسے سیمینار میں بیٹھنا ہوگا اور اس سے زیادہ حیرت اس پر تھی ڈاکٹر حمید اللہ بہت ہشاش بشاش بھی دکھائی دے رہے تھے، گویا انھوں نے پوری نیند بھی لی ہو! غازی صاحب نے کہا کہ تب مجھے معلوم ہوا کہ ’’برکت‘‘ سے مراد کیا ہے اور کسی کے وقت میں اور صلاحیت میں برکت ہوتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے! انھوں نے کہا ہمارے لیے تو وقت کے چھ گھنٹے بس چھ گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن جن کے وقت میں برکت ہوتی ہے تو ان چھ گھنٹوں کی لمبائی کے علاوہ ان کی چوڑائی اور گہرائی بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ چھ گھنٹوں میں وہ وہ کچھ کرپاتے ہیں جو ہم کئی کئی دنوں میں نہیں کرپاتے۔
میرا ناقص مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غازی صاحب کے اوقات میں بھی بڑی برکت رکھی تھی۔ اس برکت کا ایک مظہر یا شاید سبب یہ تھا کہ بہت ساری مصروفیات کے بیچ میں جیسے ہی انھیں موقع ملتا، وہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے۔ کئی کئی بار ہم نے دیکھا کہ غازی صاحب دفتر سے نکلے ہیں تو اپنی عادت کے مطابق انتہائی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف جارہے ہیں اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، مصحف نکال کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔
چونکہ غازی صاحب کو بہت زیادہ سفر بھی کرنے پڑتے تھے، اس لیے انھوں نے وقت کا ایک نہایت مفید مصرف یہ نکالاتھا کہ ایئر پورٹ پر فلائیٹ کے انتظار کا وقت وہ مطالعے میں گزارتے تھے۔ کئی کئی ضخیم کتابوں کا مطالعہ انھوں نے اس طرح کیا۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں ڈاکٹر انصاری صاحب نے انھیں استاد محترم جناب پروفیسر عمران احسن خان نیازی صاحب کی کتاب Theories of Islamic Law کے نئے ایڈیشن کی ایک کاپی تحفتاً پیش کی تو غازی صاحب نے نیازی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی اس کتاب کا مطالعہ میں نے کراچی کے ایئر پورٹ پر کیا ہے۔
غازی صاحب وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے اور ہمہ وقت اس کوشش میں مصروف رہتے تھے کہ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر انصاری صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی غیر ملکی سفر کے دوران میں جب وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے اور اتفاقاً ان کے پاس پڑھنے کے لیے کتاب نہیں تھی تو انھوں نے ہوٹل کی جانب سے کمرے میں رکھے گئے پمفلٹ اور مینو وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے۔ انصاری صاحب کہتے ہیں کہ ان کے استفسار پر غازی صاحب نے جواب دیا کہ پڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے تو یہی سہی، کچھ نہ پڑھنے سے اس کا پڑھنا بہتر ہوگا!
وسعت مطالعہ
کتابوں کی اور مطالعے کی بات چلی ہے تو غازی صاحب کی وسعت مطالعہ کے متعلق بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غازی صاحب کی دلچسپی کا میدان بہت وسیع تھا۔ علوم القرآن، حدیث، فقہ، قانون، سیرت، تاریخ، مقارنۃ الادیان، فلسفہ، زبان و ادب، معاشیات و اقتصادیات اور دیگر بہت سارے علوم پر وہ نہایت گہری نظر رکھتے تھے۔ کئی دفعہ غازی صاحب ہمیں بتایا کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے بڑے بھائی مولانا ابوالخیر مودودی نے انھیں یہ نصیحت کی تھی کہ کسی کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں کہیں سے اقتباسات پڑھنے کے بجائے اسے بائے بسملہ سے تائے تمت تک پورا پڑھا جائے۔ ڈاکٹر انصاری صاحب سے سنا کہ غازی صاحب نے خود انھیں بتایا کہ انھوں نے امام شافعی کی کتاب الأم تین دفعہ ابتدا سے انتہا تک پڑھی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتاب الأم کا علمی معیار کتنا بلند ہے اور ضخامت کے علاوہ زبان کے لحاظ سے بھی اور موضوع و مواد کے لحاظ سے بھی یہ کتنی مشکل کتاب ہے، لیکن غازی صاحب کو اس کتاب سے کچھ اور طرح کی ہی محبت تھی ( بالکل اسی طرح جیسے استاد محترم نیازی صاحب کو امام سرخسی کی کتاب المبسوط سے ہے)۔ آگے میں ذکر کروں گا کہ غازی صاحب کا ارادہ یہ تھا کہ کتاب الأم کے مختلف ابواب سے جہاد کے متعلق مباحث اکٹھا کر کے انھیں ’’سیر الامام الشافعی‘‘ کے نام سے مرتب کریں۔ معلوم نہیں کس حد تک وہ اس منصوبے پر عمل کرپائے۔
تراث کی کتابوں پر غازی صاحب کو بلاشبہ عبور تھا اور ہمارے کئی دوست جب کسی عبارت کے فہم میں کہیں مشکل محسوس کرتے تو غازی صاحب ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ میرے عزیز دوست پروفیسر ضیاء اللہ رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ ادارۂ تحقیقات اسلامی کے لیے اصول السرخسی کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے انھیں جب بھی کسی عبارت میں کہیں مشکل محسوس ہوئی تو وہ فوراً غازی صاحب کی طرف رجوع کرتے اور غازی صاحب وہیں اس مشکل کا نہایت آسان اور مناسب حل پیش کردیتے۔
جہاد و سیر کے موضوعات سے دلچسپی
جیسا کہ ذکر کیا گیا، غازی صاحب کی دلچسپی کے موضوعات تو بہت سے تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انھیں فقہ و قانون اور بالخصوص جہاد وسیر کے احکام کے ساتھ انتہائی دلچسپی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ غازی صاحب کو ڈاکٹر حمید اللہ کے ساتھ نہایت عقیدت و محبت تھی اور جہاد و سیر ڈاکٹر حمید اللہ کا پسندیدہ موضوع تھا۔ چنانچہ جب جامعہ اسلامیہ بہاولپور نے انھیں ایک سلسلۂ محاضرات کے لیے آمادہ کیا تو انھوں نے جہاد و سیر ہی کے موضوعات چنے۔ بارہ خطبات کا یہ مجموعہ پہلے ’’خطبات بہاولپور۔ ۲‘‘ کے نام سے شائع کیا گیا، کیونکہ خطبات بہاولپور کے عنوان سے ڈاکٹر حمید اللہ نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور ہی میں بارہ خطبات دیے تھے ۔ تاہم ڈاکٹر حمید اللہ کے بارہ خطبات میں ایک خطبہ ہی جہاد وہ سیر سے متعلق تھا جبکہ غازی صاحب کے بارہ خطبات تمام کے تمام جہاد وسیر سے متعلق تھے۔ کچھ عرصہ قبل شریعہ اکیڈمی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام آباد ، نے ان خطبات کو ’’ اسلام کا قانون بین الممالک‘‘ کے عنوان سے دوبارہ شائع کیا ہے ۔
غازی صاحب کا ایک نہایت وقیع علمی کارنامہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید اور اسلامی بین الاقوامی قانون کے بانی امام محمد بن الحسن الشیبانی کی شہرۂ آفاق کتاب ’’ السیر الصغیر‘‘ کے متن کی تدوین اور اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے۔ علمی دنیا میں السیر الصغیرکی اہمیت مسلم ہے کیونکہ اس کتاب میں امام شیبانی نے جہاد و سیر کے موضوع کے تمام بنیادی اور اصولی مسائل پر فقہ حنفی کی راجح اور مفتی بہ آرا ذکر کی ہیں۔ مجید خدوری نے، جو عراقی مسیحی تھے، امام شیبانی کی کتاب الأصل سے سیر، خراج اور عشر کے ابواب کا متن مدون کرکے ان کا انگریزی ترجمہ کیا تھا اور انھیں The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar کا نام دیا ۔ عام طور پر ان ابواب کو ہی امام شیبانی کی السیر الصغیر سمجھا گیا، تاہم استاد محترم غازی صاحب نے ثابت کیا کہ یہ ایک بہت بڑا علمی مغالطہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے السیر الصغیر کے متن کی تدوین اور ترجمے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ اس مقصد کے لیے ان کے سامنے دو مآخذ تھے : ایک امام الحاکم الشہید المروزی کی کتاب ’’الکافی فی فروع الحنفیۃ‘‘ جس میں امام شیبانی کی چھ کتابوں (ظاہر الروایۃ) کی تلخیص کی ہے اور دوسری شمس الائمۃ سرخسی کی کتاب ’’المبسوط‘‘ جو ’’الکافی‘‘ کی شرح ہے ۔ غازی صاحب نے واضح کیا کہ امام حاکم نے جب ’’الکافی‘‘ میں ظاہر الروایۃ کی تلخیص کا کام کیا تو چار کتابوں کو تو انھوں نے ملخص کیا، مگر سیر کے ابواب میں السیر الکبیر، السیر الصغیر اور دیگر کتب کے مواد کو ملخص کرنے کے بجائے انھوں نے السیر الصغیر کے متن کو جوں کا توں نقل کیا۔ گویا امام سرخسی کی المبسوط کی دسویں جلد میں کتاب السیر دراصل امام شیبانی کی السیر الصغیر کی شرح ہے۔ غازی صاحب نے الکافی کے مخطوطات اور المبسوط کے مطبوعہ نسخوں کا تقابل کر کے السیر الصغیر کا ایک مستند متن تیار کیا اور پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، نیز انگریزی میں ایک مبسوط مقدمہ بھی لکھا جس میں انھوں نے سیر اور بین الاقوامی قانون کے تقابل پر بھی بحث کی، سیر کی تدوین اور ارتقا کا بھی جائزہ پیش کیا اور امام شیبانی کی فقہی خدمات پر بھی روشنی ڈالی۔ ادارۂ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے غازی صاحب کی اس کاوش کو Shorter Book on Muslim International Law کے عنوان سے شائع کیا۔
۲۰۰۸ء میں غازی صاحب قطر جارہے تھے تو انھوں نے مجھے بتایا کہ سیر پر وہ دو کتابیں لکھنا چاہتے ہیں : ایک انگریزی زبان میں اور دوسری عربی زبان میں۔ انھوں نے کہا کہ انگریزی کتاب کے مخاطبین قانون کے ماہرین ہوں گے، اس لیے اس میں بین الاقوامی قانون کے مباحث زیادہ ہوں گے جبکہ عربی کتاب کے مخاطبین علمائے کرام ہوں گے، اس لیے اس کا زیادہ حصہ فقہی مباحث پر مشتمل ہوگا ۔ مجھے معلوم نہیں کہ وفات سے قبل وہ یہ کام تکمیل تک پہنچاپائے یا نہیں ۔
پچھلے سال ستمبر ۲۰۰۹ء میں ڈاکٹر انصاری صاحب نے سیر پر کام کے لیے ادارۂ تحقیقات اسلامی کے تحت ایک خصوصی گروپ تشکیل دیا جس میں انھوں نے غازی صاحب کے علاوہ پروفیسر عمران نیازی صاحب، ڈاکٹر محمد طاہر منصوری صاحب ( سابق عمید، کلیہ شریعہ و قانون، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد )، ڈاکٹر محمد منیر صاحب ( سربراہ شعبۂ قانون، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد)، ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب (سربراہ شعبہ فقہ، ادارۂ تحقیقات اسلامی) اور راقم الحروف کو شامل کیا ۔ سیر کا یہ پراجیکٹ دو طرح کے کاموں کے لیے وجود میں لایا گیا: ایک یہ کہ فقہ اسلامی کی اساسی کتب میں سیر سے متعلق مواد پر تحقیق کرکے ان کی تدوین کی جائے اور ان کا انگریزی اور اردو میں ترجمہ کیا جائے اور دوسرا یہ کہ سیر اور جہاد کے موضوعاتی مطالعے کے لیے مناسب موضوعات کا انتخاب کرکے ان موضوعات پر اس فن کے متخصصین سے تحقیق کرائی جائے۔ اس سلسلے میں غازی صاحب نے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا کہ کسی طرح کتاب الأم کے مختلف ابواب سے سیر کے متعلق مواد اکٹھا کرکے ان کی اچھی ایڈیٹنگ کی جائے اور اس طرح ’’سیر الامام الشافعی‘‘ مرتب کی جائے ۔ انھوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ پہلے ہی اس سلسلے میں کافی کام کرچکے ہیں۔ انصاری صاحب کی خواہش پر غازی صاحب نے اسی کام کی تکمیل کا ارادہ کرلیا۔ راقم کی ہمشیرہ محترمہ سعدیہ تبسم صاحبہ نے (ریسرچ ایسوسی ایٹ، ادارۂ تحقیقات اسلامی )، جو اس گروپ کی سیکریٹری ہیں، بعد میں غازی صاحب سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اپنی گوناگوں مصروفیت کے باوجود غازی صاحب اس پراجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ تاہم ان کی اچانک وفات کی وجہ سے شاید یہ کام ادھورا ہی رہ گیا ہے ۔
’’کاسموپولیٹن فقہ‘‘ یا ’’ فقہ عولمی‘‘ کا تصور
اگست ۲۰۰۹ء میں ادارۂ تحقیقات اسلامی میں ’’بر صغیر میں اسلامی قانونی فکر اور ادارے‘‘ کے عنوان سے ایک تین روزہ بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں غازی صاحب نے توسیعی خطبہ بعنوان ’’برصغیر میں مطالعہ فقہ: ماضی، حال اور مستقبل‘‘ پیش کیا۔ اس خطبے میں نہایت اہم نکات زیر بحث آگئے تھے جن میں ایک ’’کاسموپولیٹن فقہ‘‘ کا تصور تھا۔ غازی صاحب نے اس خطبے میں کہا کہ عالمگیریت (globalization)کے اثرات دیگر شعبہ ہائے زندگی کے علاوہ فقہ و قانون پر بھی مرتب ہورہے ہیں اور ایک ایسی cosmopolitan fiqh یا ’’الفقہ العولمی ‘‘ وجود میں آرہی ہے جو نہ کلیتاً حنفی ہے، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ مالکی، نہ ظاہری۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی غازی صاحب اپنے بعض محاضرات میں اظہار خیال کرچکے تھے ۔ فقہ عولمی کا یہ تصور دور رس نتائج کا حامل ہے، اس لیے بعض شرکاے سیمینار نے اس رائے کا اظہار کیا کہ غازی صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ ایک الگ نشست میں فقہ عولمی کے تصور کے خد و خال کی وضاحت کریں۔ راقم کا تاثر یہ تھا کہ فقہ عولمی کے تصور کی بنا اس امر پر ہے کہ کسی موضوع کی جزئیات کے متعلق مختلف فقہی مذاہب سے آرا اکٹھی کرکے ایک ایسی صورت بنائی جائے جو متعین فقہی مذاہب کے دائروں سے بالاتر ہو۔ اس امر کو اگرچہ بعض لوگ روشن خیالی اور معروضیت کا تقاضا، نیز بدلتے ہوئے عالمی حالات کے تناظر میں ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہیں، لیکن میری ناقص رائے میں یہ تصور اس بنا پر نہایت خطرناک ہے کہ ’’تلفیق‘‘ کے اس طریق کار کی وجہ سے قانون اصولی تضادات کا شکار ہوجاتا ہے۔ استاد محترم پروفیسر عمران احسن خان نیازی کی بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ اس موضوع پر جب ڈاکٹر غازی صاحب اپنی آرا کا اظہار کریں گے تو اس کے بعد پروفیسر نیازی ان پر اپنا تبصرہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد مذاکرے میں شریک دیگر افراد اس موضوع پر کھلی بحث کریں گے۔ یہ بھی طے پایا کہ ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری اس مذاکرے کی صدارت کریں گے اور آخر میں وہی پوری بحث کو سمیٹیں گے۔ چنانچہ ۱۵ ؍اگست ۲۰۰۹ء کو ادارۂ تحقیقات اسلامی کے سیمینار روم میں اس خصوصی مذاکرے کا اہتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں اصحاب علم نے شرکت کی۔
ڈاکٹر غازی صاحب نے فقہ عولمی کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے اسے عالمگیریت کا ایک لازمی نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمگیریت کی وجہ سے دنیا کے ایک خطے میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مسائل سے دوسرے خطوں کے مسلمان بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ ذرائع مواصلات میں بے پناہ ترقی کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں رونما ہونے والے واقعات کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی صاحب علم نے کسی مسئلے پر کوئی رائے ظاہر کی تو بہت جلد وہ دوسرے اصحاب علم تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس پر اظہار خیال شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں بحث مباحثے کے بعد بڑی حد تک ایک متفقہ رائے وجود میں آجاتی ہے۔ انہوں نے عالمگیریت سے پیدا ہونے والے مسائل اور خطرات کی بھی نشاندہی کی۔ نیز غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کے مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ معاصر دنیا کے ان مخصوص حالات کی وجہ سے مختلف میدانوں میں جو فقہ مرتب ہورہی ہے، وہ کسی خاص فقہی مذہب کی بندشوں کی پابندی سے بہت حد تک آزاد ہے، بلکہ بسا اوقات ایک ہی مسئلے کے مختلف جزئیات میں مختلف مذاہب کی آرا کو جوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح ایک نئی فقہ وجود میں آجاتی ہے۔ انہوں نے اس کو ’’Fiqhi Engineering‘‘ کا نام دیا اور اس سلسلے میں بالخصوص اسلامی بینکاری کی مختلف پراڈکٹس کی مثالیں دیں۔
پروفیسر نیازی نے اس تصور پر تبصرہ کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کیا کہ جسے فقہ عولمی کہا جارہا ہے، پہلے اس کے اصول متعین کرنے چاہئیں کیونکہ فقہ کی بنیاد اصول فقہ پر ہے، اس لیے فقہ عولمی کی تشکیل سے پہلے فقہ عولمی کے اصولوں پر بحث ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصول میں بہت کچھ مشترک ہے اور ان مشترک اصولوں کی بنیاد پر عصر حاضر میں فقہ کے ایک بڑے حصے کی مشترکہ تشکیل کی جاسکتی ہے، لیکن اصولوں کی بحث میں پڑے بغیر اگر صرف سہولت اور آسانی کی خاطر یا دنیوی اغراض کے حصول کے لیے مختلف فقہی مذاہب سے ’’Pick and choose‘‘ کیا جائے گا تو اس ’’تلفیق‘‘ کے اثرات بہت خطرناک نکلیں گے، کیونکہ اس طرح جو چیز وجود میں آئے گی، وہ اصولی تضادات کی وجہ سے عملی دنیا میں پنپ نہیں سکے گی۔ انہوں نے کہا جسے غازی صاحب نے ’’Fiqhi Engineering‘‘ کہا، وہ دراصل ’’Reverse Engineering‘‘ ہے کیونکہ اسلامی بینکاری والے کرتے یہ ہیں کہ غیر اسلامی بینکوں کے ایک پراڈکٹ کو سامنے رکھ کر اس کو سند جواز عطاکرنے کے لیے اس پراڈکٹ کی مختلف جزئیات کے جواز کے متعلق مختلف فقہی مذاہب کی آرا اکٹھی کردیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر قرار دیتے ہیں کہ یہ پراڈکٹ شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے۔ پروفیسر نیازی نے مزید کہا کہ ایک فقہی مذہب دراصل ایک مستحکم قانونی نظام ہوتا ہے جو بعض مخصوص اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ایک جزئیے میں حنفی رائے لی گئی اور دوسری میں شافعی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک جگہ آپ ’’عام‘‘ کو قطعی کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہ ظنی، ایک جگہ آپ قول صحابی کو حجت مان رہے ہیں اور دوسری جگہ اس سے انکار کررہے ہیں۔ یہی وہ اصولی تضادات ہیں جن کی وجہ سے تلفیق اور فقہ عولمی کا تصور ناقابل قبول اور ناقابل عمل بن جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک فقہی مذہب میں بھی بعض اوقات ایک سے زائد آرا پائی جاتی ہیں، لیکن ’’فتویٰ‘‘ کے لیے ان میں سے ایک کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ’’تخییر‘‘ کہتے ہیں اور اس کے اپنے اصول ہیں۔ تخییر محض ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر نہیں کی جاسکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقلید کو خواہ مخواہ تنقید کا نشانہ بنایاجاتا ہے، حالانکہ کسی بھی مستحکم قانونی نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تقلید کے اصول کو مانا جائے۔ انہوں نے ماتحت عدالتوں پر اعلیٰ عدالتوں کے نظائر کی پابندی کو تقلید کی بہترین مثال قرار دیا۔ اس موقع پر غازی صاحب نے کہا کہ وہ فقہ عولمی کے تصور کے نہ داعی ہیں اور نہ وکیل، بلکہ وہ صرف ایک مبصر اور شاہد کے طور پر وہ کچھ بیان کررہے ہیں جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔
بطور معلم
غازی صاحب کی شخصیت کے یوں تو کئی پہلو تھے، لیکن درحقیقت وہ اولاً و آخراً ایک معلم تھے۔ کسی بھی موضوع پر گفتگو سے پہلے وہ کوشش کرتے تھے کہ مخاطبین کی نفسیات اور علمی استعداد کا اچھی طرح جائزہ لیں، پھر اپنے طلبا کی ذہنی سطح تک آکر انھیں بتدریج اپنے ساتھ علمی رفعتوں تک لے جاتے۔ قدرت نے انھیں مشکل سے مشکل موضوع کو آسان اور سلیس زبان میں بیان کرنے کا عجیب ملکہ عطا کیا تھا۔ یونیورسٹی میں میرے ابتدائی دور سے ہی مختلف سیمینارز میں انھیں بارہا سننے کا موقع ملا اور جب بھی انھیں سنا کوئی نئی بات سیکھی یا پرانی بات یاد آئی یا اس پر از سرنو غور کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ان کی کتابوں کا علمی مقام تو ہے ہی ارفع، لیکن طلبا کے لیے خاصے کی چیز ان کا سلسلۂ محاضرات ہے جس میں ان کے محاضرات کو تحریری قالب میں ڈھال کے شائع کیا گیا ہے۔ محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت، محاضرات شریعت، محاضرات فقہ اور محاضرات معیشت و تجارت میں غازی صاحب ایک مثالی معلم کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ان محاضرات میں دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک نہایت قابل رشک خصوصیت یہ ہے کہ ہر ہر محاضرہ میں کمال درجے کا ربط و نظم پایا جاتا ہے جس سے متعلقہ موضوعات کے اطراف و جوانب پر غازی صاحب کی گہری نظر کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ بات صرف محاضرات کی حد تک ہی صحیح نہیں ہے جن کے لیے وہ بہر حال کچھ تیاری کرکے آتے تھے (اگرچہ اس تیاری کا ماحصل صرف چند نکات میں کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر غازی صاحب اپنی وضع کردہ مختصر نویسی کے ذریعے محفوظ کرلیتے تھے)، بلکہ اگر انھیں اچانک ہی کسی موضوع پر بولنے کے لیے کہا جاتا تو لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ اچانک یوں منظم و مرتب طریقے سے اس موضوع پر بولنا شروع کردیتے کہ گویا انھوں نے اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں اسی موضوع پر پہلے سے کوئی مخصوص فائل محفوظ کی ہوئی ہو جسے اب انھوں نے کھول کر پڑھنا شروع کردیا ہو۔
یوں تو ۱۹۹۴ء سے ہی، جب میں نے اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقتاً فوقتاً غازی صاحب سے بہت استفادہ کیا لیکن ۲۰۰۷ ء میں جب میں نے فقہ میں تخصص کے لیے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا تو ان کے سامنے باقاعدہ زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ ایک سمسٹر میں ان سے دو کورسز پڑھے اور، الحمد للہ، بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ۔ پی ایچ ڈی کی اس کلاس میں ہم صرف تین طلبا تھے۔ ہم غازی صاحب کے دفتر میں ہی کلاس لیتے تھے جو لیکچر کے بجائے علمی مباحثے کی صورت میں ہوتی تھی۔ غازی صاحب کی مہمان نوازی سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے کیونکہ وہ ہمیں کافی بھی پلایا کرتے تھے اور مباحثہ بھی جاری رہتا تھا۔ بعض اوقات تو ہم اس مخمصے میں پڑ جاتے کہ کافی کی وجہ سے مباحثے نے زیادہ لطف دیا یا مباحثے کی وجہ سے کافی بہت اچھی لگی !
ایک مثالی معلم ہونے کی وجہ سے غازی صاحب کو اپنے طلبا کے ساتھ نہایت محبت تھی۔ ۲۰۰۶ ء میں جب صدر جامعہ کے طور پر ان کے عہدے کی مدت پوری ہوئی تو انھوں نے کلیہ شریعہ میں باقاعدہ کورسز پڑھانے شروع کردیے تھے اور اس سلسلے میں انھوں نے ایسی کوئی قید بھی نہیں رکھی کہ وہ صرف پی ایچ ڈی کے طلبا کو پڑھائیں گے، حالانکہ اگر وہ ایسا کرتے تو قانون کے تحت یہ ان کا حق تھا، بلکہ انھوں نے ایل ایل ایم کو بھی کورسز پڑھائے اور ایل ایل بی کو بھی۔ بالخصوص ایل ایل بی کے طلبا و طالبات جن کو اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں ہی غازی صاحب جیسا معلم نصیب ہوا، وہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھے۔ میری ہمشیرہ محترمہ سعدیہ تبسم صاحبہ نے اسی دور میں غازی صاحب سے فقہ العلاقات الدولیۃ کا کورس پڑھا۔ وہ ذکر کرتی ہیں کہ کلاس میں غازی صاحب نے صرف یہی نہیں کیا کہ متعلقہ موضوع پر لیکچر دے کے چلے جاتے، بلکہ انھوں نے مختلف طریقوں سے طالبات کی علمی استعداد بڑھانے کی طرف توجہ دی اور بالخصوص کوشش کی کہ ہر ہر طالبہ عربی صحیح بولے اور لکھے۔
میں اسے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل سمجھتا ہوں کہ شاگردوں کے ساتھ غازی صاحب کی اس خصوصی محبت کا مجھے وافر حصہ ملا۔ جولائی ۲۰۰۶ء میں جبکہ وہ صدر جامعہ تھے اور اس وجہ سے ان کی مصروفیات میں گوناگوں اضافہ ہوا تھا۔ ایک دن انھوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حدود کے متعلق جناب ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صاحب کی کتاب پر میرا تبصرہ ان کی نظر سے گزرا اور وہ انھیں بہت پسند آیا ہے۔ پھر انھوں نے مجھے ترغیب دی کہ جو نکات اس تبصرے میں اٹھائے گئے ہیں، ان کی وضاحت کے لیے باقاعدہ ایک کتاب لکھوں۔ اس ترغیب کے نتیجے میں ہی حدود پر میں نے کتاب لکھی جو اگست ۲۰۰۶ء میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب جب غازی صاحب کی خدمت میں پیش کی تو انھوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ دنوں بعد جب پارلیمنٹ نے تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا تو کلیہ شریعہ کے طلبا و اساتذہ نے اس ایکٹ پر بحث کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ راقم کو اس قانون کے شق وار تجزیے کی ذمہ داری دی گئی۔ میرے مقالے سے پہلے غازی صاحب نے حدود قوانین کا ایک عمومی جائزہ پیش کیا اور اس کے بعد انھوں نے اس ناچیز کا ذکر جس محبت کے ساتھ کیا، وہ میرے لیے ایک سرمایۂ افتخار ہے۔
۲۰۰۸ء کے اوائل کی بات ہے۔ ایک دن میں سٹاف روم میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں شعبۂ فقہ کے اساتذہ کی میٹنگ ہورہی ہے۔ میں معذرت کرکے واپس ہوا لیکن غازی صاحب نے مجھے آواز دے کربلایا اور اپنے قریب بٹھا کر کہا کہ آپ کی آمد اس وقت ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ پھر دیگر اساتذہ کی طرف رخ کرکے کہا کہ ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کام کس کو سونپا جائے، لیکن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ سوچ بچار سے بچالیا ۔ پھر میرے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا : یتولاہ القوی الأمین۔
کچھ عرصہ قبل جب غازی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج کی ذمہ داری سونپی گئی تو انھوں نے فوراً ہی اسلامی قانون کی روشنی میں مجموعۂ تعزیرات پاکستان کی بعض دفعات کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں مجھے بھی انھوں نے عدالت کے معاون کے طور پر طلب کیا۔ یونیورسٹی میں مصروفیت کی وجہ سے میں عدالت تاخیر سے پہنچا اور پہلے دن کی سماعت پوری ہوچکی تھی۔ میں واپس ہوا تو ظہر کی نماز کے بعد غازی صاحب کا فون آیا اور انھوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اکتوبر کے مہینے میں ہر ہفتے چار دن اس کیس کی سماعت کریں گے اور تعزیرات پاکستان کی بعض دفعات نہیں بلکہ پورے مجموعۂ تعزیرات کا جائزہ لیں گے۔ انھوں نے زور دے کر کہا کہ کلیۂ شریعہ کے بعض ہونہار طلبا و طالبات میں اس کام کو تقسیم کرکے عدالت کا کام آسان کیا جائے۔ غازی صاحب کی وفات کے ایک دو دن بعد مجھے عدالت کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ اکتوبر سے اس کیس کی سماعت شروع ہونے والی ہے اور میں اس سوچ میں پڑگیا کہ غازی صاحب ہوتے تو یہ کام کیسے ہوتا اور اب جبکہ وہ نہیں رہے تو ان کے بعد یہ کام کیسے ہوپائے گا ؟ اچانک حدیث مبارک یاد آگئی :
ان اللہ لا ینتزع العلم من الناس انتزاعاً، ولکن یقبض العلماء فیرفع العلم معھم و یبقی فی الناس رءوساً جھالاً یفتونھم بغیر علم فیضلون و یضلون (صحیح مسلم ، باب رفع العلم و قبضہ و ظہور الجہل و الفتن، حدیث رقم ۴۸۲۹)
کیا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، بالخصوص کلیۃ الشریعۃ و القانون غازی صاحب کی علمی خدمات کے اعتراف میں ’’غازی چیئر‘‘، ’’غازی ایوارڈ‘‘ اور ’’غازی لیکچرز‘‘ کا اہتمام کرسکے گی؟
معدوم قطبی تارا
ڈاکٹر شہزاد اقبال شام
(۳ اکتوبر ۲۰۱۰ء کو الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں کی جانے والی گفتگو جسے مصنف کی نظر ثانی کے بعد شائع کیا جا رہا ہے۔)
محترم جناب مولانا ابوعمار زاہد الراشدی صاحب،
برادرم مولانا مفتی محمد زاہد صاحب اور معزز خواتین و حضرات!
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ زندگی بھر میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے، لیکن کبھی کبھی میرے لیے مشکلات بھی کھڑی کر دیتے تھے۔ ان میں سے دو ایک کا ذکر تو آگے چل کر کروں گا۔ فوری طور پر تو یہ کہ ان کے اس دنیائے فانی سے اچانک رخصت ہوجانے کے بعد آج ان کی نسبت سے میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ مجھے ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی ہے جو خود فصاحت وبلاغت کا مرقع تھا۔ اور جو شخص فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہو، اس کی شخصیت پر گفتگو کرتے وقت انصاف کا دامن تھامنا دیہاتی پس منظر کے حامل میرے جیسے شخص کے لیے خاصا مشکل کام ہے۔ ان کی قدرت کلام اور میری بے ربط باتوں میں آپ کو وہی فرق دیکھنے کو ملے گا جو امریکہ اور ویت نام کی ٹیکنالوجی کے درمیان ہے۔ ڈاکٹر غازی مرحوم کی وفات نے میرے لیے یہ ایک مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اس کے باوجود جس کسی نے بھی محترم عمار ناصر کو میرے بارے میں بتایا کہ وہ مجھے یہاں خطاب کا شرف بخشیں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کے ساتھ میرے نیاز مندانہ تعلق کے حوالے سے اس شخص کا انتخاب غلط نہیں ہے۔
جب مجھے مولانا موصوف کے حوالے سے فون آیاتو مجھے تعجب ہوا اور پریشانی بھی ہوئی کہ اس کڑے امتحان سے کیسے نکلوں گا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اور میرے درمیان کچھ نہ کچھ مشترک چیزیں رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ میڈیا بیزار آدمی تھے اور میں بھی ہجوم اور مجمع سے دور رہنے کا عادی ہوں۔ شاید ہی کوئی کہہ سکے کہ میں نے اس طرح کے مجمع عام میں کبھی تقریر یا خطاب کیا ہو، اگرچہ پیشہ کے لحاظ سے استاد ہوں۔ لیکن مجھے یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی توقع پردو وجوہ کے باعث تسلی ہوئی کہ ایک تو یہ کہ ایک امید موجود ہے۔ روزِ محشر جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں ،کہ وہ ستارالعیوب ہے اور دعا ہے کہ روزِمحشر کو وہ ہماری خامیوں پر پردہ ڈالے اور یہ بھی دعاہے کہ قیامت کے دن ہماری خوبیوں کو ظاہر کرے۔ میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس توقع کے ساتھ یہاں حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو اتنے سارے انفس متبرکہ بیٹھے ہیں کہ میں انہیں یہاں گواہ بنا کر اور گواہی دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کردار کی کس بلندی پر تھے۔
۲۶ ستمبر کی صبح کو ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب نے غالباً مجھے سب سے پہلے فون پر ان کی رحلت کی اطلاع دی تو میں گھر کے باہر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹرفاروقی صاحب شریعہ اکادمی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں اور بہت ہی نیک سیرت، سچے اور امانت دار شخص ہیں۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو چیخ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب! آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، میں یہی سمجھا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے فون بند کر دیا۔ اپنے اطمینان کے لیے میں نے ڈاکٹر غازی صاحب کے گھر فون کیا تو معصوم بچی کی معصوم سسکیوں نے خبر کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد میں نے چند دوستوں کو اطلاع دی اور ڈاکٹر صاحب ؒ کے گھر جانے کی تیاری کی چونکہ ان کے ساتھ ہمارے دیرینہ خاندانی مراسم تھے، اس لیے جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے ڈاکٹر غزالی صاحب کو گلے لگا یا اور دھاڑیں مار نے کو دل چاہا تو پتہ چلا کہ غزالی صاحب صبرو استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ جب میری اہلیہ ڈاکٹرصاحبؒ کے گھر کے اندر گئیں تو واپسی پر انہوں نے بتایا کہ اتنا بڑا صدمہ سہنے کے باوجود ڈاکٹر صاحبؒ کی والدہ محترمہ تعزیت کو آنے والوں کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ؒ موصوف سے میری پہلی ملاقات ۳۰؍ ستمبر ۱۹۸۱ء کو تب ہوئی جب میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں داخلہ کے لیے گیا۔ وہ اس کمیٹی میں تھے جو امیدواروں کا انٹر ویو کررہی تھی۔ اس کمیٹی کے تین ارکان تھے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تینوں کے نام محمود تھے۔ ان میں ایک محمود شرف الدین، مصری استاد تھے اور اب بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کو طویل زندگی دے۔ دوسرے رکن پروفیسر سید احمد محمود ، علی گڑھ سے پڑھے ہوئے استاد تھے۔ اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے ۔ اور تیسرے ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ تھے۔ اللہ سے التجا ہے کہ وہ انہیں اپنے قریب جگہ دے۔
جب ان لوگوں نے انٹرویو کر لیا تو من جملہ دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر غازی صاحبؒ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اگر آپ کو شریعہ کی بجائے اصولِ دین میں داخلہ دے دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ ’’اصول دین میں میرا میلان نہیں ہے‘‘۔ پوچھا: ’’فقہ پر کوئی کتاب پڑھی ہے‘؟‘ ان دنوں میں سرعبدالرحیم کی کتاب ’’اصول فقہ اسلام‘‘ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا: ’’سرعبدالرحیم کی کتاب ’’اصول فقہ اسلام‘‘ پڑھ رہا ہوں‘‘۔ یوں داخلہ ہو گیااور میں چار سال تک اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحبؒ کی علمی پختگی نے ہم سب کو خرید لیا۔
چار سال بعد ایل ایل ایم میں داخلے کے لیے انٹرویو ہوا۔ حسب دستور پھر ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوا۔ اس کمیٹی میں بھی ڈاکٹر غازی صاحبؒ موجود تھے۔ اس میں ڈاکٹر حسین احمد حسان جو بعد میں اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے، موجود تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایل ایل ایم میں داخلہ لینے آئے ہو (بات عربی میں ہورہی تھی) تو شرکات کی قسمیں بتائیں۔ میں نے شرکۃ الصنائع سے شروع کیا، حالانکہ ترتیب تو کچھ اور تھی۔ شرکۃ الابدان تک پہنچاتو تیسری قسم یاد نہ آئی۔ تھوڑا ادھر ادھر دیکھا، گلے میں اٹکا تھوک نگلا تو شرکۃ الوجوہ یاد آگئی۔ اب چوتھی قسم یاد نہ آئے۔ پھر ادھر ادھر دیکھا۔ معلوم ہوا، ڈاکٹر غازی صاحب منہ میں کچھ بدبدا رہے ہیں۔ ہونٹوں کی جنبش اوپر نیچے دکھائی دی تو معلوم ہوا ’’میم‘‘ کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح میرے ذہن میں مفاوضہ کا لفظ ابھرا جو میں نے ادا کیا اور یوں میرا داخلہ ہو گیا۔ فی الحقیقت ڈاکٹر صاحب ہر کسی کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ دینے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اسی لیے اس انٹرویو میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات ایک اور مثال سے زیادہ واضح ہو گی۔
ابھی چھ ماہ پہلے ڈاکٹر صاحبؒ نے مجھے کہا کہ ملک سے باہر کچھ وقت لگا آؤ، تاکہ نیا کلچر اور نیا رنگ دیکھنے کو مل جائے۔ میں نے ایک برطانوی یونیورسٹی کی ایک خالی اسامی کے لیے درخواست دی۔ آپ کو پتہ ہے بیرون ملک اس قسم کے کاموں کے لیے کسی حوالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ کام بالعموم استاد کے ذمے ہوتا ہے، لہٰذا ایک رائے تو آپ دیں۔ انہوں نے فوراً قطر سے اس یونیورسٹی کو خط لکھ دیا۔ میں نے پوچھا : ’’دوسرا خط کس سے لوں؟‘‘ بولے ’’سید سلمان ندوی صاحب سے لے لیں‘‘۔ میں نے کہا : ’’سید سلمان ندوی صاحب سے میرے کوئی زیادہ علمی مراسم نہیں رہے، اس لیے آپ انہیں کہہ دیں‘‘۔ کہنے لگے : ’’وہ میرے کہے بغیر خط دے دیں گے‘‘۔ پوچھا: ’’یہ کیسے ممکن ہے‘‘؟ بولے ’’بس ویسے ہی دیں گے بغیر علمی مراسم کے‘‘۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہنے لگے : ’’دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو، جو ’’سید ‘‘ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اگر مجھے بھی شامل کرنا چاہو تو بیان یوں ہو گا کہ جوشخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہو، سچی محبت کرنے والا ہو، وہ ہمیشہ نفع دے گا۔‘‘ ندوی صاحب نے واقعی خط دیا۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہی ان کے زیادہ قریب تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ موصوف کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ سورج کو باہرکھڑے ہو کر دیکھیں تو ہر آدمی یہ تصور کرے گا کہ یہ سورج سب سے زیادہ اسی کے قریب ہے۔ دلی میں بیٹھا ہوا شخص بھی یہی خیال کرتا ہے اور کابل میں بیٹھا ہوا بھی یہی خیال کرتا ہے کہ سورج بس میرے لیے ہے۔ ڈاکٹر صاحبؒ کی صورت حال بھی کچھ ایسی تھی کہ ان سے جو بھی ملتا تھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ میرے سے زیادہ کسی کا اکرام نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ سبھی کے ساتھ برابر ہوتا تھا۔
یہاں میں سامعین کو ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ یہ گفتگو منتشر یادداشتوں کے مجموعے میں سے کچھ یادوں کی ضوفشانی ہے۔ میں بس واقعات بیان کرتا جاؤں گا، نتائج آپ خود نکالیں۔
ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پولیس اکیڈمی میں لیکچر ہے اور میں نے کہیں ضروری اجلاس میں جانا ہے، آپ میری جگہ پر جاکر لیکچر دے دینا۔ پندرہ سال قبل کا واقعہ ہے۔ تب میں قدرے نوآموز تھا، اس لیے پریشان ہوا کہ وہاں پر پولیس آفیسر آتے ہیں، سینئر لوگ ہوتے ہیں، شاید انصاف نہ کر سکوں۔ خیر چلا گیا اور آج پندرہ سال سے وہاں ان کی نیابت کر رہا ہوں۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ ان کا وہ مخصوص انداز تھا جس کے تحت وہ اپنے ساتھیوں کو بغیر چونکائے، بغیر احساس دلائے آگے بڑھاتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس میں سے ایک واقعہ مزید سن لیجیے۔
جنوری ۲۰۰۰ء میں جنوبی افریقہ میں وہاں کے مسلمان قانون دان اور اکاؤنٹنٹس کی ایسوسی ایشن معروف بہ ایسوسی ایشن آف مسلم اکاؤنٹنٹس اینڈ لائیر، ڈربن نے جو وہاں کی ایک مشہور تنظیم ہے، ایک سیمینار کیا۔یہ سیمینار اسلامی یونیورسٹی کے تعاون سے تھا۔ موصوف نے مجھے اس کا آرگنائزر مقرر کیا اور بیشتر امور میرے سپرد کر دیے۔ لیکچرار حضرات کا انتخاب بڑی حد تک میرے ذمہ تھا، اگرچہ ان سے مشاورت ایک بدیہی امر تھا۔ تنظیم نے ہمیں فقہ اور شریعت پر لیکچر دینے کے لیے کہا تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا کہ دو چار ساتھی تیار کر لیں اور میں خود بھی تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحبؒ جمہوری نظر یہ کے آدمی تھے۔ ایک آدمی کے بارے میں مجھے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا ۔ ’’ڈاکٹر صاحب، اسے چھوڑیں‘‘۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا۔ تیسری دفعہ فائل لے کر گیا تو میں نے کہا : ’’ڈاکٹر صاحب میں اسے نہیں لے جاؤں گا، اسے چھوڑیں‘‘۔ میں غلطی پر نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے اورلگتا تھا کہ طبیعت پر جبر کر کے میری بات مان لی، حالانکہ مذکورہ شخص منصب کے لحاظ سے ان کے برابر کا تھا اور میرا دفتری قد کاٹھ اتنا نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی جسارت پاکستانی دفتری نظام میں کر سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مکمل آزادی رائے، آزادی اظہار اور آزادی عمل دیا کرتے تھے۔
آگے سنیے! عین وہ دن جب افتتاحی تقریب تھی ۲۰۰۰ء میں عیدالاضحی کے ایک دن بعدتو عیدالاضحی سے ایک دن پہلے یونیورسٹی تو بندتھی، لیکن دفاتر کھلے تھے۔ ہمیں اپنے ایک دوست ڈاکٹر انواراللہ صاحب حال مقیم برونائی دارالسلام کے ویزا کی مشکلات تھیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر غازی صاحب اس وقت نیشنل سیکورٹی کونسل کے رکن تھے اور اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کونسل وفاقی کابینہ سے بھی اوپر ایک ادارہ تھا۔ گویا اس کے ارکان وفاقی وزرا سے بھی بلند منصب کے حامل تھے۔ مختلف امور کی انجام دہی کے لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو تقریباً تیس بار ۔۔۔جی ہاں تیس بار ۔۔۔ٹیلی فون کیا اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے دفتر میں بیٹھے ہونے کے باوجود انہوں نے ہر بار میری بات کو سنا اور پوری رہنمائی فرمائی۔ حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کا مزاج ایسا ہے کہ اگر ایک دفعہ ، دو دفعہ، تین دفعہ سے زیادہ چوتھی دفعہ فون سننا پڑ جائے تو اکتا جائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحبؒ نے دفتر میں بیٹھے ہونے کے باوجود ہر دفعہ پوری طرح بات کو سنا اور رہنمائی کی۔ مجال ہے کہ ان کے لب ولہجہ میں کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہو۔ مجال کہ یہ کہا ہو ، بھائی خود جاؤ، خود کرو، تنگ کر رہے ہو، بلکہ پوری رہنمائی کرتے رہے کہ فلاں کو فون کرو، فلاں سے پوچھو، اب فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے بعد فلاں کے پاس جاؤ۔ یہ ان کی تحمل مزاجی کی صرف ایک مثال ہے۔
جب سارا کام مکمل ہو گیا اور عید گزر گئی تو مجھے کہنے لگے: ’’میری سیٹ ادھر ادھر کر دو، میں عیدالاضحی کے تین دن بعد آؤں گا‘‘۔ اب میرے چھکے چھوٹ گئے۔ میں نے کہا: ’’افتتاحی تقریب میں جنوبی افریقہ کا چیف جسٹس ہوگا، آپ نہیں جائیں گے تو میں کیا کروں گا‘‘۔ ڈاکٹر صاحبؒ ایسے مواقع پر زیادہ بولتے نہیں تھے۔ کہنے لگے: ’’چونکہ آپ کو اس سے پہلے فلپائن وغیرہ میں جانے سے کام کا تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ چلے جائیں، میں تین دن بعد آ جاؤں گا‘‘۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق اکیلے ہی چلا گیا اور جنوبی افریقہ میں وہاں کے چیف جسٹس کے زیرصدارت منعقدہ تقریب میں میں نے ڈاکٹر غازی صاحب کی نیابت کی۔ بعد میں معلوم ہو اکہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کا آدمی کو آگے بڑھانے میں ایک مخصوص اسٹائل تھا۔
ان کے کردار کی پاکیزگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں وہاں ڈربن میں اس ہوٹل کے استقبالیہ کے پاس لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا جہاں ہم سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں اپنے ملک میں تو ہر ہوٹل پر فائیو اسٹار لکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فائیو سٹار ہوتا کیا ہے، لیکن وہ کوئی ایکڑوں پر محیط تھری سٹار ہوٹل تھا جس میں لوگ میلوں کے حساب سے چہل قدمی کرتے تھے ۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اتفاق سے یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں [ الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ کے تہہ خانہ میں] اس ہوٹل کے لاؤنج جیسی ہے ۔یہی سمجھ لیں مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو گی۔ یوں ان سیڑھیوں کے سامنے ایک آئینہ لگا ہوا تھا اور استقبالیہ پر ایک سفید فام افریقی نژاد لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ جنوبی افریقہ میں اکثریت سیاہ فام آبادی کی ہے، تاہم اقلیت میں تقریباً ۳، ۴ فی صد گورے افریقی بھی ہیں۔ بہرحال وہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی جس کی عمر تقریباً ۳۰،۳۲ سال ہوگی، کھڑی تھی۔ آج سے پیچھے جنوری ۲۰۰۰ء میں چلے جائیں تو ڈاکٹر صاحبؒ کی عمر اس وقت تقریباً ۴۹ سال کی تھی۔ یہ کوئی ایسی عمر نہیں ہے، جس کو بڑھاپے پر محمول کیا جائے اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کی صحت تادمِ رحلت بہت اچھی تھی۔ اب ہوا ایسے کہ جوں ہی ڈاکٹر صاحب کی نظر اس خاتون پر پڑی تو انہوں نے فوراً آنکھیں نیچی کر لیں۔ میں سب کچھ آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے آئینہ میں نوٹ کی۔ دنیا کا کوئی دوسرا جاننے والا شخص وہاں پر دیکھنے والا نہیں تھا اور ڈاکٹر صاحب کو وہاں میری موجودگی کا نہ تو علم تھا اور نہ میں ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ انہیں علم ہو سکتا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر غیرمحرم پر پہلی نظر غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر پڑ جائے تو معاف ہے، دوسری کا مواخذہ ہو گا۔ اس موقع پر میں نے دیکھا کہ اس سارے عمل میں ڈاکٹر صاحب میں کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ پھر وہ فطری طریقے پر رواروی میں ہمیں تلاش کرتے کرتے میز پر آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔
آپ خواتین و حضرات کو گواہ بنا کر میں اللہ کی عدالت میں ان کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔
ڈاکٹر صاحب مالی معاملات میں بھی بڑے دیانت دار تھے۔
۱۹۹۹ء میں یکم اگست سے ا۳؍ اگست تک ایک عدالتی پروگرام چلانے کے لیے فلپائن میں جانے کا ہوا۔ فلپائن کے اس سفر کی مثال ، میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں گویا کراچی ائیرپورٹ پر اترے۔ اگلی فلائٹ سے پشاور میں پہنچے، پھر بس یا کار میں پشاور سے کالام پہنچے۔ اس طرح فلپائن میںآپ گویا منیلا میں بذریعہ ہوائی جہاں اترے، پھر پشاور جیسے ایک چھوٹے شہر زیمبوانگا میں بذریعہ ہوائی جہاز اترے اور وہاں سے بذریعہ بحری جہاز ایک اور چھوٹے بلکہ بہت ہی چھوٹے شہر میں جاپہنچے۔ وہ جگہ آخری جزیرہ ہے جس کے بعد ایک جزیرہ چھوڑ کر ملائشیا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں ہم نے جانا تھا، وہاں جنگلات تھے اور دن میں آٹھ گھنٹے بجلی بند رہتی تھی۔ ٹی وی نشریات کوئی نہیں تھیں بلکہ وہ کیبل پر چلتا تھا۔ ٹیلی فون لینڈ لائن کوئی نہیں تھی، صرف موبائل فون تھے۔ اخبار تین دن بعد پہنچتا تھا۔ یوں سمجھیے جو درمیانی شہر ہے جس کی مثال میں نے پشاور دی ہے، وہاں تک تو ہم بذریعہ ہوائی جہاز پہنچے۔
ڈاکٹر غازی صاحب نے خود ہفتہ دس دن بعد آنا تھا۔ اس درمیانی شہر سے اصل جگہ تک جانے کے لیے اٹھارہ گھنٹے تک ہماری سوزوکی نمابحری جہاز میں سفر ہوتا تھا۔ جہاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تقریباً پانچ چھ سو لوگ سفر کرتے تھے۔ اس منظر کشی کے بغیر شاید میں بات واضح نہ کر سکوں۔ اس میں جتنے بھی مسافرہوتے تھے ، ان کی لباس کی ہیئت کچھ اس طرح تھی کہ دیسی زبان میں ہم اسے نکر یا ’’کاچھا‘‘کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس طرح کا مختصر لباس پہنا ہوا تھا۔ لوگ عام نچلے طبقے کے ماجھے گامے تھے۔ تہذیب سے دور، کوئی سوشل لائف نظر نہیں آتی تھی۔ آپ خود ان لوگوں کے بارے میں اندازہ کر لیں کہ کس طرح کے لوگ ہوئے ہوں گے۔ عام سوسائٹی کے لوگوں میں غالب اکثریت عیسائی تھی۔ درمیانی شہر سے سوزوکی نماجہاز مغرب کے بعد وہاں سے چلا اور اگلے دن ظہر اور عصر کے درمیان اپنی منزل کو پہنچا۔ اس درمیانی شہر سے ۱۳؍ نشستوں والا ایک ہوائی جہاز بھی ہماری منزل تک چلتا تھاجوصرف چار دن چلتا تھا :غالباً پیر، منگل ، جمعرات اور جمعہ۔
یہ بات ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے۔ وہاں پر سیٹوں کا کچھ مسئلہ پیدا ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا:’’آپ نے مجھ پر جو بندشیں لگائی ہوئی ہیں، ذرا سی تو کم کریں۔ سیٹیں مل نہیں رہیں اور لوگوں کی فلائٹ تبدیل کرنی ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، مجھے ایک ٹیلی فون کی اجازت دیں تو میں منیلا میں پاکستانی سفارت خانے سے کہہ دوں‘‘۔ کہنے لگے :’’نہیں ، نہیں، عام پاکستانی کی طرح رہا کریں اور عام پاکستانی کی طرح زندگی گزارا کریں، سفارت خانے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑا کریں‘‘۔ میں چپ ہو گیا۔ ہاں تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ واپسی پر ان کے شیڈول کے مطابق ہوائی جہاز موجود تھا، اس جگہ آتے ہوئے تو وہاں کی انتظامیہ اور لوگوں نے ٹکٹ دیا تھا۔ واپسی کا ٹکٹ شریعہ اکیڈمی کے ذمہ تھاجس کا ذمہ دار میں تھا ۔ میں نے کہا : ’’ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا پاسپورٹ دیں‘‘۔ پوچھا: ’’کیا کرنا ہے‘‘۔ میں نے کہا : ’’ آپ کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینا ہے‘‘۔ بولے: ’’ارے نہیں! میں بحری جہاز پر واپس پر جاؤں گا‘‘۔
اس جہاز کی سونے والی نشست کا منظر کچھ یوں تھاکہ اس کی چوڑائی بہت ہی کم تھی اور پھر ایک نشست کے اوپر تلے کل تین آدمی سوتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر کروٹ لینا ہوتی تو آدمی پہلے اٹھ بیٹھتا اور پھر اپنی کروٹ بدلتا تھا۔ میں نے کہا : ’’ڈاکٹر صاحب !اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ۔ آپ ہوائی جہاز پر آرام سے جائیں‘‘۔ بولے: ’’میں جہاز پر جا کر کیا کروں گا‘‘ ۔ مجھے پتہ تھا کہ اس جہاز پر سفر کرنا نہایت مشکل ہے۔ میرے ضد کرنے پر بولے :’’آپ چھوڑیں، مجھے یہ سب معلوم ہے اور میں گزشتہ سال دعوہ اکیڈمی کے ایک پروگرام میں اس بحری جہاز پر سفر کر چکا ہوں‘‘۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ ہوائی جہاز میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ تقریباً۲۵۰۰روپے پاکستانی، جب کہ بحری جہاز میں۷۰۰/۸۰۰روپے لگتے ہیں، یعنی اسی طرح دونوں کے کرایے میں کوئی اٹھارہ سو پاکستانی روپے کا فرق تھا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو بغیر تقریر کیے مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ نہ یہ کہا کہ قوم کا پیسہ ہے، خون پسینہ کی کمائی ہے، کوئی حدیث نہیں سنائی، کوئی لیکچر نہیں دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی اس مسکراہٹ کے بارے میں انہیں کہا کرتا تھا: ’’ اسے ’’تبسم سقم شناس‘‘ کہنا مناسب ہے‘‘ؒ ۔وہ انسان کی غلطی محسوس کرنے کے بعد ہلکا سا مسکراتے تھے، پھر بات کا رخ دوسری طرف بدل دیتے تھے ۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے :’’ بھائی ! بحری جہاز میں دو چار کتابیں پڑھ لوں گا، کیا ضرور ہی سونا ہے؟‘‘ مجھے یہ بھی معلوم تھا، انہیں بھی پتہ تھا کہ وہاں اس بحری جہاز میں تو ۱۵، ۲۰ واٹ کا بلب لگا ہوا تھا، وہاں تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ میں حیران تھا کہ آپ پہلے بھی سفر کر چکے تھے اور یہ جانتے بھی تھے۔ سپریم کورٹ کے جج تھے، اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، یونیورسٹی کے وائس پریذیڈنٹ تھے۔ ذرا دوسری طرف ملک کے عدالتی نظام کے سب سے نچلے پرزے، سول جج کے بارے میں آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اعلیٰ حضرت کی تشریف آوری پر کیا کیا ہاہا کار مچتی ہے۔ استحقاق کے سوال جنم لیتے ہیں۔ ٹی اے ڈی اے کی جمع تفریق ہوتی ہے۔ اے اللہ !میں گواہی دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس جہاز پر پاکستان کے کسی بالکل عام شخص کی طرح سفر کیا ،حالانکہ وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے۔
جب وطن واپس پہنچے تو ہمارے ٹی اے ڈی اے کا حساب ہوا۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ پوری دیانت داری سے اپنا اور ان کا بل ڈائریکٹر فائنانس کے پاس بھیجاجو ان کے ماتحت تھے۔ اس نے کوئی دس ہزار روپے کم کر دیے اور غلط کم کیے۔ میں فائل اٹھا کر ان کے پاس چلا گیا اور کہا : ’’آپ ڈائریکٹر فنانس کو سمجھا نہیں سکتے ، اس نے دس ہزار کی کٹوتی کی ہے‘‘۔ بولے : ’’چھوڑو، اب اس نے لکھ لیا ہے، میں اس کو کیا کہوں‘‘۔ پہلے تو میرے دل میں ملال ہوا کہ دس ہزار روپے کم ہورہے ہیں، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ میرے تو صرف دس ہزار روپے کم ہو رہے ہیں، ان کے تو تقریباًبیس ہزار کے لگ بھگ کم ہورہے ہیں، لہٰذا چپ ہو گیا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی یادیں توبہت ہیں، لیکن ترتیب سے بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے ۔ ممکن ہے کہ آپ اس بات کو پسندنہ کریں کہ میری گفتگو بے ربط ہے اور اس میں ترتیب نہیں ہے، لیکن آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے بیان کر رہا ہوں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ کو گواہ بنا کر بیان کیا ہے۔
یہاں ایک ضروری بات بیان کرنا اہم ہے۔ پھر میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا۔
آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام میں رجال کی کتابوں میں بہت سی جگہوں پرخاص طورپر تراجم کے اثاثہ میں، کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خاصی افراط وتفریط ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے جیسے کسی نادان طالب علم کو استاد یا شیخ کے ساتھ اتنی محبت اور تعلق ہو گیا ہوتا ہے کہ اسے ان کی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ پس یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے معاملے میں میرے ساتھ ایسے نہیں ہے، اس کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔
ویسے تو میں نے ان سے کئی بار اختلاف کیا، لیکن دو تین واقعات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ امریکی دستورمیں ایک عبارت Chosen Representatives of Congress کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک تحریر میں ’’کانگریس کے چنیدہ ارکان‘‘ کیا۔ مجھے ایک تحریر لکھنے کا موقع ملا تو میں نے اس اپنی تحریر میں لکھا کہ ’’سپریم کورٹ کے ایک جج نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جو آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں‘‘۔
دراصل جمہوریت کے بارے میں ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر تھا جو یہ تھا کہ جمہوریت ومہوریت ایسے ہی ہے۔ سوسائٹی پر رول کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے سوجھ بوجھ رکھنے والے اور پڑھے لکھے افراد استحقاق رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس عبارت کا ترجمہ بھی تقریباً یہی کیا ہے کہ امریکی دستوریہی کہہ رہا ہے کہ منتخب ارکان نہیں، بلکہ چنیدہ ارکان ہوں گے اور چنیدہ میں کسی اور طریقے سے چنے گئے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ ان کی تشریح ہو ا کرتی تھی۔ میں نے جب تحریر لکھی تو اس پر گرفت کی اور لکھا کہ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج یہ تشریح کرتے ہیں حالانکہ امریکی دستوری تاریخ کے سوا دوسو سال میں کسی امریکی جج یا کانگریس کے کسی رکن نے آج تک یہ تشریح نہیں کی ہے جس طریقے سے ڈاکٹر غازی صاحب تشریح کر رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی اس فلٹر سے گزر کر کانگریس تک نہیں پہنچا، اس لیے ڈاکٹر غازی صاحب کی تحریر محل نظر ہے۔ میں نے یہ تحریر اسی طرح اپنے ایم فل کے مقالے میں بھی لکھی۔ جب میں یہ تحریر ان کے پاس لے کر گیا اور انہوں نے کہاکہ آپ کا مقالہ ٹھیک ہے۔ میں نے مذکورہ نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ، ’’ذرا اس بات کو غور سے پڑھیں‘‘۔ بولے : ’’ہاں، یہ بھی ٹھیک لکھا ہے‘‘۔
دوسرا واقعہ سن لیجیے اور ضمناً میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر میں کہوں کہ وہ خطاؤں سے خالی تھے تو یہ ایمانیات سے متصادم گفتگو ہو گی۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی زندگی میں دو شخص ایسے دیکھے ہیں جو بشری کمزوریوں کے باوجود بہت سی ناروا چیزوں سے خالی تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ڈاکٹر صاحب کی کمزوریوں پر گرفت کی۔ اکثر اوقات تو اس کی وضاحت کر دیتے جس سے آدمی مطمئن ہو جاتا تھا۔ مثلاً یونیورسٹی میں ایک شخص کی تقرری ہوئی جو میرے نزدیک نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ تقریباً تمام افراد کی رائے یہی تھی کہ وہ شخص سسٹم سے باہر کا ہے تو اس کو اس سسٹم میں کیوں لایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس چلا گیا تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے۔
ذرا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امور سلطنت چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم اخباروں میں کیا کچھ لکھ دیتے ہیں، منبر رسولؐ پرمائیک مل جائے تو کیا کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اس واقعے میں دراصل ایک صاحب تھے جو باربار میرے پاس بار بار آ رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مجھے اپنے پاس غیر ملکی طلبا والے سنٹرمیں استاد رکھ لو۔ میں اس وقت دعوۃ اکیڈمی کی طر ف سے اس سینٹر کاپرنسپل تھا۔ میں نے کہا کہ اب وقت گزر چکا ہے،کہاں رکھ لوں۔ اب ٹائم ٹیبل بھی بن چکا ہے۔ وہ صاحب ایک بڑے آدمی کی سفارش لکھوا کر لے آئے ، انکار کر دیا۔ پھر دوسرے کی لائے، پھر انکار کیا۔ پھر تیسرے کی ، میں نے پھر انکار کر دیا۔ حتی کہ ڈاکٹر غازی صاحبؒ کی لائے جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل یعنی افسر اعلیٰ تھے۔ پھر بھی میں نے انکار کردیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور بولے : ’’میں بہت سی جگہوں پر جواب دہ ہوں، حتیٰ کہ صدر کوبھی ، وزیراعظم کو بھی وغیرہ۔ خیر یہ آدمی تو مولانا وصی مظہر ندوی کا ہے، اگر مولانا مجھے شام کو مل گئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ اس کا بندوبست کر دو تو بہتر ہے‘‘۔ یہ سنتے ہی میں نے اس شخص کا الٹا سیدھا بندوبست کر دیا۔
حقیقت یہ ہے کہ اب اسلامی یونیورسٹی وہ نہیں رہی جو آج سے دس پندرہ سال پہلے تھی۔ اس میں تدریج کے ساتھ علمی اور اس کی روایات کے لحاظ سے ہر آنے والے لمحہ میں ضعف آتا گیا اور آچکا ہے۔ ایسا ہی ضعف ان کے دور میں بھی آتا گیا۔ ایک دن ڈاکٹر غازی صاحب نے Islamic Jurisprudenceیعنی اصول فقہ اور اسلامیات سے متعلقہ اساتذہ کو بلایا۔ ہال بھرا ہوا تھا اور اکثراساتذہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر غازی صاحب کے ایک طرف ڈاکٹر فضل الٰہی (احسان الٰہی ظہیر کے بھائی جو سعودی عرب سے پڑھے ہوئے ہیں ) اور دوسری طرف پروفیسر یوسف کاظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ من جملہ دیگر باتوں کے ڈاکٹر غازی صاحب کی منظر کشی اور طلاقت لسانی کسی حد تک زبان زدعام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں اساتذہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا :’’یہ دونوں حضرات حرمین شریفین میں رہ چکے ہیں۔ یہ میری بات کی تصدیق کریں گے‘‘۔ اس کے بعد اپنی گفتگو کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ عربی زبان پڑھنے کی افادیت اپنی جگہ تو مسلم ہے، لیکن انگریزی زبان بھی سیکھنا ہمارے لیے فرض کفایہ ہے ۔ اور کہا کہ تمام اساتذہ یہ دونوں کورس انگریزی ز بان میں پڑھائیں۔ اگر نہیں پڑھا سکتے تو اپنی انگریزی کو پالش کریں اور کورس انگریزی ہی میں پڑھائیں۔
ڈاکٹر صاحب کافی دیر تک انگریزی زبان میں کورس پڑھانے کے بارے میں بات کرتے رہے ۔ میرا ذاتی نظریہ یہ تھا کہ ہم لوگ علوم اسلامیہ کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں جو عربی ز بان میں ہیں جس کی کمیت میں ہر آنے والے لمحے میں یعنی تقریباً پچھلے پانچ سال سے اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب انگریزی زبان کے بارے میں رطب اللسان تھے اور مجھے پوری حقیقت کا علم نہیں تھا کہ پیچھے تاریں کون ہلا رہا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ حقیقت تو بہت بعد میں جسٹس خلیل الرحمن صاحب نے بتائی کہ گزشتہ دنوں اس وقت کے انتہائی بدبخت صدر مملکت کی ہدایت پر یہ سب کچھ احتیاط سے کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں، میں سوال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک دفعہ بٹھایا تو تھوڑی دیر بعدمیں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کر میرا ایمان بڑھ گیا ہے اور تازہ ہوا ہے۔ آج کے بعد مجھے جتنی انگریزی آتی ہے، اس کو مزید پالش کروں گا۔ تاہم آخر میں ، میں نے کہا :’’ڈاکٹر صاحب ! ایک گزارش کروں گا ۔ آپ ہی سے پڑھا ، سنا ہے کہ امام شافعیؒ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور اب آپ بتائیں کہ اگر فرض عین اور فرض کفایہ میں تعارض ہو تو کس کو ترجیح حاصل ہو گی‘‘۔ میں نے مزید کہا : ’’آپ کے یہاں ہر آنے والے لمحے میں عربی میں ضعف آ رہا ہے‘‘ ۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ لاجواب ہو گئے۔ ادھر نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور یوں اجلاس ختم ہوگیا۔
میری اس بات کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان سے گفتگو میں جیت گیا ، بلکہ یہ واقعہ سنانے کامقصد یہ ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کومحض عقیدت نہ سمجھ لیں۔ میں ان سے کھل کر اختلاف بھی کیا کرتا تھا۔یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ ان کے کردار کی بلندی اور عظمت کے گوشے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ لوگ میری گواہی پر گواہی دے سکیں۔
اسی طرح ان کی علمی بلندی کی ایک بات سن لیجیے۔ میرے اور ان کے درمیان علمی لحاظ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ میں پچھلے کافی عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہوں ، لا گریجویٹ ہوں ، لائسنس لینے کے لیے کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی ہے ۔ اس نسبت سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تقریباً ڈیڑھ درجن کے قریب جج حضرات سے قریبی مراسم ہیں۔ ان سے قانونی گفتگو ہوتی رہی ہے، قانون پڑھاتا ہوں، لیکن پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان سارے جج حضرات کے علم کو ایک طرف رکھ دیں اور ڈاکٹر صاحب کا انگریزی قانون سے متعلق جو علم تھا، اس کو دوسری طرف رکھ دیں تو ان جج حضرات کا علم ڈاکٹر صاحب کے علم کے مقابلہ میں پرکاہ جیسا بھی نہیں ہے ۔
میں نے ۱۹۹۳ء میں ایک ادارے میں ایک قانون پڑھانا شروع کیا اور اس قانون کا نام صنعتی قانون تھا۔یہ قانون عام لا کالجوں میں پڑھائے جانے والے قوانین سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے۔ اس میں اہم صنعتی قوانین شامل تھے۔ ملک میں بہت سے آرڈیننس نافذ ہیں جو سارے کے سارے نہیں پڑھائے جاتے بلکہ تعلیمی زندگی میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ قانون کہاں سے تلاش کریں۔ کچھ بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں، لیکن سارے قوانین نہیں پڑھائے جا سکتے۔ اس ادارے میں ایسے ہی دس بارہ قانون تھے جو میں نے کبھی سنے بھی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ایک قانون Payment of Wages Act یعنی اجرتوں کی ادائیگی کا قانون ہے۔ یہ قانون فیکٹری اور کاروباری اداروں میں کام کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ ایک اور قانون میں دیگر باتوں کے ساتھ ایک ترکیب illegitimate son and daughter یعنی ناجائز بیٹا اور بیٹی ہے جن کا قانون کے تحت صنعتی کارکن کی وراثت میں حصہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں کس طرح ممکن ہے کہ ناجائز بیٹے اور ناجائز بیٹی کو وراثت میں حصہ ملے۔ میں نے اپنے سے بہتر اہل علم اور جج حضرات سے دریافت کیا، تاہم کسی نے تشفی نہیں کرائی اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ ادھر ڈاکٹر غازی صاحب بنیادی طور پر عربی زبان میں ڈاکٹریٹ تھے۔ انہوں نے مجھے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ دو بجے رات تک فون کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ساری زندگی اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس دن میں تنگ آگیا تھا کہ صبح کو لیکچر ہے اور میں ان طلبہ کو کیا پڑھاؤں گا۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لفظ illegitimate کا ترجمہ بتا دوں گا۔ پاکستانی طلبہ خاموشی سے سن لیتے ہیں اور اگر کوئی بات کرے بھی تو استاد ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہے ، میں بھی اسی طرح کروں گا۔ لیکن پھر سوچا کہ ڈاکٹر غازی صاحب سے پوچھ لوں جو آخری اوزار تھے۔ یقین کیجیے، انہوں نے مجھے دو تین منٹ میں یوں چٹکی میں سارا مسئلہ سمجھا دیا۔ اب آپ کے ذہن میں تجسس پیدا ہو رہا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے، آپ بھی سن لیں۔
یہ قانون انگریزوں کا وضع کردہ قانون تھا۔ ملک میں جس طرح انگریزوں کے دیگر قانون چل رہے ہیں، یہ قانون بھی چل رہا تھا۔ اب اس کا مرتبہ کیا ہے ؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ قانون اور ایک دوسرا قانون سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا جہاں اسے غیراسلامی قرار دے دیا گیا تھا۔ اصل میں جب فوجی لوگ گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر مشقیں کرتے ہیں تو اس دوران میں فصلوں وغیرہ کا نقصان ہوتا ہے تو ان کا اسٹیشن ہیڈکوارٹر لوگوں کی تلافی کرتا ہے۔ ایک دفعہ جب ایسی ایک ادائیگی کا موقع آیا تو اس دوسرے قانون میں بھی ناجائز اولاد کا بطور وارث ذکر موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے بتایا کہ کچھ دوسرے لوگ جو ناجائز اولاد تھے، وہ ورثا کے طور پر کھڑے ہو گئے اور قانون سامنے رکھ دیا۔ یہ قانون شرعی عدالت سے ہوتے ہوتے سپریم کورٹ گیاتوفیصلہ یہ ہوا ہے کہ قانون تو یقیناًموجود ہے مگر یہ غیر شرعی قانون ہے۔ چنانچہ یہ قانون تو اب تک موجود ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، لکھا ضرور ہے ۔ گویا اس مسئلے کی حالت ناسخ و منسوخ کی سی سمجھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا تجزیہ ۱۹۹۳ء میں کیا جب وہ یونیورسٹی میں محض ایسوسی ایٹ پروفیسر عربی تھے۔جج وہ ۱۹۹۹ء میں بنے تھے۔ اس وقت وہ ایک عام سے استاد تھے۔ عربی زبان پڑھاتے تھے۔ فقہ پڑھاتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ قانونی نظائر کے رسائل کا وہ تسلسل کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے۔
ڈاکٹر غازی صاحب کس قدر نیک سیرت تھے ، کیا بتاؤں۔ میری معلومات کے مطابق قرآن کی سات منازل جو غالباً حضرت عثمانؓ کی طرف سے مقرر کر دہ ہیں، موصوف روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے او ر یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ دن بھر وہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اگرچہ دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے۔
سامعین کرام! کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ میرے لیے بہت صدمہ ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ وہ رخصت ہو گئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو میری سمجھ سے بالا ہے کہ کیوں اتنی جلدی ان کی شام زندگی ہمیں دیکھنے کو ملی؟ لیکن سامعین کرام! ان کی وفات میں ایک مثبت پہلو بھی ہے جو شاید میں آپ سب لوگوں کو نہ سمجھا سکوں، لیکن سرکاری لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اسلام آباد میں لوگ ساٹھ سال عمر پوری کر کے ریٹائر ہو تے ہیں، لیکن باوسیلہ خواتین و حضرات کا ایک پورا غول پیر تسمہ پاکی طرح ہرطرف مسلط ہے۔ ان میں سے بیشتر کی عمر آج ۸۰، ۸۵ سال تک ہے ۔ مخلوق خدا ان کو کوستی رہتی ہے کہ مرتے کیوں نہیں اور کہتی ہے کہ یہ لوگ ہٹتے کیوں نہیں ہیں۔ کئی اصحاب تو منہ میں دانت نہ پیٹ میںآنت کے مصداق نماز کے دوران میں جس کرسی پر رکوع و سجود کرتے ہیں، میں نے اس کرسی کو بھی چرچرا کر غالباً کوستے سنا، لیکن حضرات ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایک ریٹائرڈ آدمی ایسا بھی ہے کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ’’ عمرہوئی تیری سو، ہنڑتاں مغروں لوہ‘‘ یعنی تمہاری عمر سو سال ہو گئی ہے، اب تو پیچھا چھوڑو۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے بیشتر کے لیے میں نے لوگوں کو ہاتھ الٹے کر کے کوسنے دیتے سنا۔
سامعین کرام! ذرا توجہ فرمائیں، غور کریں۔ غازی صاحب بھرا میلہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اورمیرے یہ دوسرے ممدوح ؟ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، افلا یعقلون۔
۱۸؍ ستمبر کو ڈاکٹر صاحب کی ساٹھویں سال گرہ تھی۔ سرکاری اعتبار سے Joining time ہفتہ دس دن ہوتا ہے۔ وہ جائننگ ٹائم انہوں نے وفاقی شرعی عدالت میں گزارا۔ ساٹھ سال پورے ہوئے تو اللہ کی جواررحمت کو جائن کر لیا۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے طمانیت ہوتی ہے کہ اللہ کے مقرب بندے تھے، مخلوق خدا کی بددعاؤں سے بچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خود دار آدمی تھے۔کبھی خود کو کسی منصب کے لیے انہوں نے پیش نہیں کیا۔
میں اسی بیان پر اپنی بات ختم کرتا ہوں حالانکہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔
میرے غازی صاحب
ڈاکٹر حیران خٹک
’’کل نفس ذائقۃ الموت‘‘ اس میں شک ہی کیا ہے۔
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
جو کوئی بھی اس دارفانی میں آتا ہے ،اسے ایک دن دارِ بقا کی طرف کوچ کرنا پڑتاہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کرگئی۔ یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے بچھڑ جائیں گے، لیکن لگتا ہے انہیں خود جانے کی جلدی تھی، اس لیے بہت کم وقت میں دینی اور دنیاوی لحاظ سے طویل سفر طے کیا۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ مزید تعلیم جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی اور مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی سے حاصل کی۔ کسی اسکول یا کالج میں ایک دن گئے بغیر ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مراحل طے کیے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی میں ریڈر کی حیثیت سے شامل ہوئے اور پھر دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل، بین ا لاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے نائب صدر ، صدر اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اپیلٹ بنچ کے جج اور آخر میں شریعت کورٹ کے جج کے منصب تک پہنچے۔ اسلامی بینکاری اور اسلامی نظام معیشت میں دنیا بھر میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے۔ سپریم کورٹ کے اپیلٹ بنچ میں جب ربا کیس سنا جارہا تھا تو ڈاکٹر غازیؒ اس بنچ کے رکن تھے اوراس بنچ نے جو تاریخ ساز فیصلہ سنایا، وہ بقول جسٹس خلیل الرحمن خان اگر ان کو ڈاکٹر غازی کی معاونت حاصل نہ ہوتی تو وہ یہ فیصلہ کبھی نہ لکھ پاتے۔
جانے والے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ بلاشبہ ڈاکٹر محمود احمدغازیؒ کی رحلت اُمت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے، لیکن میرے لیے ذاتی طور پر بہت بڑا نقصان ہے، میں ایک ہمدرد اور غمگسار بزرگ سے محروم ہوگیاہوں۔
مجھے دعوۃاکیڈمی میں لانے والے وہی تھے۔ انہی کی دعوت پر میں نے پشاور کوخیرباد کہا۔ انہوں نے دعوۃ اکیڈمی میں قیام کے د وران اور اس کے بعد مجھے بہت عزت دی۔ جب دعوۃ اکیڈمی سے ان کاتبادلہ بحیثیت نائب صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہوگیا تو انہوں نے میرے تبادلے کی تجویز بھی بھیجی، لیکن اُس وقت کے ڈائریکٹر جنرل محترم ڈاکٹرانیس احمد صاحب نے اس تجویزسے اتفاق نہیں کیا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے پھر میرا تبادلہ شعبہ امتحانات میں کردیا۔ اب کی بار میری مرضی بھی اس میں شامل تھی چنانچہ محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے بھی جانے کی اجازت دے دی۔
ڈاکٹر غازیؒ درویش صفت انسان تھے۔ اگرچہ وہ ملنے ملانے میں زیادہ گرم جوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق ان کے ساتھ بے تکلفی برتتا۔ کبھی کبھی یہ بے تکلفی بے ادبی کی حدود کو بھی چھو لیتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب میرے مزاج سے بخوبی واقف تھے، اس لیے میر ی باتیں خندہ پیشانی سے برداشت کرلیتے۔
ڈاکٹر غازیؒ مجھ پر بہت اعتماد کرتے تھے اور الحمدللہ میں نے کبھی ان کے ا عتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ ایک دفعہ وہ کہیں بیرونِ ملک تشریف لے جارہے تھے اور میرا تربیت اساتذہ کا پروگرام شروع ہونے والا تھا۔ چنانچہ میں نے شرکا کی تعداد کے مطابق خالی اسناد ان کے سامنے دستخط کرنے کے لیے رکھ دیں ۔ انہوں نے خالی اسناد کو دیکھا اور کہا کہ ’’خالی اسناد پر دستخط کرنے پڑیں گے‘‘؟ میں نے کہا مجبوری ہے، چنانچہ ہماری مجبوری کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے خالی اسناد پر دستخط ثبت کیے۔ جب میرا تبادلہ شعبہ امتحانات میں ہواتو میں ایک دفعہ پھر براہِ راست غازی صاحبؒ کے ماتحت ہوگیا۔ وہ ان دنوں یونیورسٹی کے نائب صدر (اکیڈمکس) تھے۔ شعبہ امتحانات میں چونکہ آئے روز نت نئے مسائل کا سامنا ہوتا تھا، اس لیے غازی صاحبؒ کے ساتھ مشاورت کے لیے میں جب بھی جاتا تو وہ نہایت مصروف ہوتے اور بات نہ ہوپاتی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دس منٹ دے دیں تاکہ میں اپنے مسائل آپ کے گوش گزار کروں۔ اس دوران پہلے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ غازی صاحب فائلیں نکالنے میں مصروف تھے۔ میری باتوں پر بھی وہ’’ بہت اچھا‘‘، ’’ٹھیک ہے‘‘ کہتے رہے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ایک دفعہ سر اٹھا کر کہا کہ دس منٹ میں سے پانچ منٹ تو آپ بول چکے۔ میں نے کہا میں توبول چکا ہوں، لیکن کیا آپ سن چکے ہیں؟ اس پر وہ مسکراکر پھر اپنے کام میں مصروف ہوگئے۔
اسی طرح ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پی ایس کے کمرے میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ انتظار کررہا تھا کہ اتنے میں غازی صاحبؒ اپنے دفتر سے برآمد ہوئے اور اپنے پی ایس سے جاتے جاتے کہا کہ اچھا میں جا رہا ہوں، کوئی کام تو نہیں ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ مجھ سمیت وہاں موجود دوسرے احباب نے یہ بات بہت محسوس کی اور ہر ایک ناگواری کا اظہارکرنے لگا۔ مجھے غازی صاحبؒ سے یہ توقع نہیں تھی، چنانچہ اگلے دن میں ان سے ملنے دوبارہ گیا۔ اس دن ان کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ جاتے ہی میں نے سلام کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کل کیاکیا؟ آپ کے اس رویے کی وجہ سے کئی احباب کی دل شکنی ہوئی، فریادیوں میں، میں بھی شامل تھا ۔چونکہ میں نے بات تھوڑی سی سخت کی تھی، اس لیے ڈاکٹرصاحبؒ کے چہرے پرکچھ ناگواری کے آثار نظر آئے۔ چنانچہ ان کے تاثر کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ ’’پیروں کو مناسب نہیں کہ مریدوں کے دلوں کو دکھائیں‘‘۔ اس پر وہ نارمل ہوگئے اور مسکرا کر کہا کہ آئندہ میں خیال ر کھوں گا اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔
جن دنوں غازی صاحب نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر بن رہے تھے تو میرے پاس ایک’’ فرشتہ‘‘ آیا اور غازی صاحب کے متعلق مختلف قسم کے استفسارات کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اگلے دن ان سے ملاقات میں عرض کیا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیاتھا جو آپ کے متعلق مجھ سے استفسارات کر رہا تھا۔ ا نہوں نے مسکرا کر کہاکہ اچھا آپ کے پاس بھی پہنچ گیا تھا اور پھر کہا کہ کئی دوستوں کے پاس یہ فرشتے پہنچ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ جس دن ان کے سیکورٹی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کی خبر شائع ہوئی تو میں مبارکباد دینے کے لیے ان کے آفس گیا۔ جب میں نے مبارکباد دی تو انہوں نے مسکراکر وصول کی اور زبان سے کچھ نہیں بولے۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے پیشکش تواس دن ہوئی تھی جس دن آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا، لیکن میں نے احباب کے ساتھ مشورے کی مہلت مانگی تھی، چنانچہ کئی دوستوں سے مشورے کے بعد آج حلف اٹھارہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ شاید کوئی خیر کا کام مجھ سے کروائے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا بیگم عطیہ عنایت اللہ اور صاحبزادہ امتیاز کے درمیان بیٹھ کر آپ اپنے خیر کے تصور کے مطابق کوئی کام کرسکیں گے؟ کہنے لگے نہ کرسکا تو چھوڑ کر آجاؤں گا۔ اب میں نے چبھتا ہوا جملہ کہا۔ میں نے کہا کہ’’ لوگ کہتے ہیں جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنی شیروانی ڈرائی کلین کرا لیتے ہیں‘‘۔ اس پر ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور کہا کہ ’’میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک نہ کسی عہدے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی کسی عہدے کے لیے کسی کو درخواست کی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہونا چاہیے‘‘ اور پھر اپنے بریف کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ’’ اگر میں اس میں پڑی ہوئی تحریر یں دکھا دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آخر یہ شخص سکون کی نیند کیسے سوتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے ان چیزوں کی پروا نہیں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے‘‘۔
وفاقی وزیر کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحبؒ نے اصلاح احوال کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ مدارس کی اصلاح کے پروگرا م میں حکومتی پروگرام سے اختلاف کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر داخلہ کے ساتھ کابینہ کے اجلاس میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی شدید خواہش تھی کہ سپریم کورٹ کے اپیلٹ بنچ کے ربا کے متعلق فیصلے کی روشنی میں پاکستان میں غیر سودی نظام معیشت رائج کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حتمی تاریخ کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن بیوروکریسی اور سیکولر عناصر نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور حکومت نے اس فیصلے کوبالائے طاق رکھ دیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ وہ کوئی مثبت کردار ادانہیں کرسکتے تو استعفا دینے میں ہی عافیت سمجھی۔
میں ان سے اکثر ذاتی اور دفتری معاملات اور مشکلات کا ذکر کرتا تھا ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ’’ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ ان تمام چیزوں کو من اللہ سمجھیں گے اور پھر کسی سے شکایت کی بجائے مشیت اللہ پر صابر و شاکر ہوں گے‘‘۔ انہوں نے کہا کہ ’’آپ یہ بات اپنے دل میں راسخ کرلیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو ذرہ برابر شر پہنچاسکتی ہے اور نہ ہی خیر‘‘۔
ڈاکٹر محمود احمدغازیؒ ایک انسان تھے اور انسان معصوم عن الخطاء نہیں ہوسکتا، لیکن امانت و دیانت کے لحاظ سے غازی صاحبؒ جن بلندیوں پر فائز تھے، ان کا اس دور میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غازی صاحبؒ اس لحاظ سے گفتار کے نہیں کردار کے غازی تھے اور انہوں نے عملی طور پر یہ بات سمجھائی کہ امانت اور دیانت کسے کہتے ہیں۔ میں ایسے کئی واقعات کا عینی شاہد ہوں۔
ایک دفعہ میں ڈاکٹر صاحبؒ کے پاس ان کے دفتر میں بیٹھا تھا کہ وہ گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بریف کیس کھول کر اس میں اپنی چیزیں رکھنے لگے۔ سامنے سے ایک پنسل اور ربر اٹھائی اور بریف کیس میں رکھ لی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ۔ کہنے لگے یہ میں اپنے ذاتی کام کے لیے گھر سے لایاہوں۔
اسی طرح ایک دن کی بات ہے۔ غازی صاحب کو کہیں باہر دورے پر جانا تھا۔ میرے سامنے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور ہدایت کی کہ کل دفتر کی گاڑی گیراج کر لیں اور اگر گھریلو ضرورت کے لیے گاڑی درکار ہو تو غزالی صاحب کی گاڑی استعمال کر لیں۔
غازی صاحبؒ یونیورسٹی کے نائب صدر بنے تو بھی میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں ان سے ملنے گیا، اندر پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے، چنانچہ میں ان کے سیکرٹری طاہر فرقان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اندرسے کچھ کاغذات فوٹو کاپی کے لیے آئے جن پر غازی صاحبؒ نے تحریر کیا تھا: ’’ذاتی‘‘۔
دعوۃ اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب حافظ بشیر احمد صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل بن کر آئے تو کئی مہینے ان کے گھر کے فون کا بل نہیں آیا۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ سر! آپ کے گھر کے فون کا بل نہیں آرہاتو انہوں نے کہا کہ’’ میرے گھر پر کوئی سرکاری فون نہیں ہے۔ میں نے ذاتی لگوایا ہوا ہے، وہی استعمال کرتا ہوں، میرے بچے بھی وہی استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتاہے کہ ایک آدھ فون دفتری مقاصد کے لیے بھی ہو جائے‘‘۔ ڈاکٹر صاحبؒ گھر کی سیلنگ بھی نہیں لیتے تھے حالانکہ قانوناً ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن وہ اخلاقی طور پر اس کو مناسب خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ تو تفریح الاؤنس بھی نہیں لیتے تھے بلکہ مہمانوں کی خاطر داری اپنی جیب سے کرتے تھے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل اور وفاقی وزیر کی حیثیت سے ان کو کافی مراعات حاصل تھیں، لیکن انہوں نے ان مراعات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسلامی یونیورسٹی میں صدر کے منصب سے ان کو جس دن فارغ کیا گیا، اُس دن وہ اپنے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب کی گاڑی میں گھر گئے اور یونیورسٹی کی گاڑی استعمال نہیں کی۔
یہ ۱۹۹۴ء کی بات ہے۔ غازی صاحبؒ اور ہمارے دو اور ساتھی کسی بین الاقوامی پروگرام میں شرکت کے لیے بیرونِ ملک جارہے تھے۔ میرا بھی تربیت اساتذہ کا پروگرام شروع ہونے والا تھا، اس لیے میں رہنمائی کے لیے غازی صاحب کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں معاً میرے دل میں بیرونِ ملک جانے کی خواہش نے سر اٹھایا۔ جب میں غازی صاحبؒ کے دفتر میں داخل ہوا تو اُن کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی وہ خط مجھے پکڑا دیا اور کہا، بھئی میں باہر جارہا ہوں۔ یہ فجی میں ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کے رابطہ کار آپ ہوں گے‘‘۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات طے کرنے کے لیے متعلقہ تنظیم سے رابطہ کرلیں۔ مجھے ملنے سے پہلے ہی وہ مذکورہ خط مجھے مارک کرچکے تھے۔ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری وہ خواہش کتنی جلد مقبول ہوئی کہ ادھر دل میں خواہش پیدا ہوئی، اُدھر اللہ نے غازی صاحبؒ کے دل میں اس کام کے لیے میرا نام ڈا ل دیا۔ یہ ایک مہینے کا پروگرام تھا اور غازی صاحبؒ کے لیے اتنا عرصہ ملک سے باہر رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ دس دن کی تاخیر سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔غازی صاحبؒ کے آنے سے پروگرام کا لطف دوبالا ہوگیا۔ غازی صاحبؒ کے روزانہ ایک یا دو لیکچرز ہوتے تھے، باقی اوقات میں خوب گپ شپ رہتی۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں پہلے بھی بے تکلف تھا، اب بے تکلفی اور بڑھ گئی۔
فارغ اوقات میں مختلف قسم کے سوالات جھاڑتا اور غازی صاحبؒ مسکرا مسکرا کر ہرسوال کا جواب دیتے۔ اس دوران غازی صاحبؒ کے ساتھ مختلف ضیافتوں اور فجی کے مختلف علاقوں کے دوروں کے مواقع بھی میسر رہے۔ ایک دن فجی مسلم لیگ کے یوتھ ونگ نے فجی کے دارالحکومت سووا کے قریب ایک جزیرے پر پکنک کا پروگرام بنایا۔ ہم پروگرام کے شرکا کے ہمراہ کشتی کے ذریعے روانہ ہوگئے۔ چونکہ کشتی نے بحرالکاہل کے سینے کو چیرنا تھا، اس لیے ہمیں لائف بوٹس دی گئیں۔ میں نے لائف جیکٹ مضبوطی کے ساتھ پہن لی۔ ڈاکٹر صاحب ؒ نے مسکرا کر کہا کہ یہ جیکٹ آپ کا بوجھ نہیں سہار سکے گی۔ میں نے استفسار کیا کہ بحرالکاہل کی گہرائی کتنی ہوگی؟ کہنے لگے کہ اوسطاً ایک سو دس میل۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہوگئے۔ انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں۔ جب ہم جزیرے پر پہنچے تو پروگرام کے شرکا بار بی کیو کی تیاری میں مصروف ہوگئے اور ہم ادھر ادھر جزیرے میں چہل قدمی کرنے لگے۔ اتنے میں کھانا تیار ہوگیا، ہم نے ڈٹ کر کھاناکھایا ۔ کھانا کھاتے ہی ڈاکٹر صاحبؒ کی طبیعت بوجھل ہوگئی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگے قیلولے کے بغیر بات نہیں بنے گی اور پھر وہیں گھاس پر کہنی سے سرہانہ بنا کر سو گئے۔ وہاں کے لوگوں کے کھانے کا ٹیسٹ بڑا مختلف تھا۔ وہ اپنے ذوق کے مطابق کھانا دیتے جس میں اکثر اوقات ابلے ہوئے چاول اور مچھلی کا شوربہ ہوا کرتا تھا جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو جب اس ناپسندیدگی کا پتہ چلا تو انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہم جو بھی پروگرام کریں گے، متعلقہ تنظیم کو بتادیں گے کہ وہ ہمارے رابطہ کار کی پسند کا خیال رکھے۔ کھانا ڈاکٹر صاحبؒ کو بھی پسند نہیں تھا لیکن خوش دلی سے اپنی ضرورت کے مطابق کھالیتے تھے۔
ایک دن ہم کھانے کے لیے بیٹھے۔ غازی صاحبؒ بھی موجود تھے۔ میں نہایت نیم دلی اور قدرے توقف سے ابلے ہوئے چاول چمچ میں اٹھا لیتا۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے مجھے کہا کہ مچھلی لے لیں! میں نے انکار میں سر ہلایا تو انہوں نے مچھلی کی ایک بوٹی اٹھائی اور کہا کہ میری خاطر ایک بوٹی لے لیں۔ چنانچہ ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے وہ بوٹی کھالی ۔
فجی کے پروگرام سے و ہ بہت خوش تھے۔ اس پروگرام میں قریبی جزائر کے دعوتی کارکن بھی شامل تھے جن کی کل تعداد ۶۰ سے زیادہ تھی۔ڈاکٹر صاحبؒ نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے انگریزی میں لیکچر دینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ مجھ میں انگریزی بولنے کی استعداد نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کا نام لے کر لیکچر دیں، آپ کی استعداد خود بخود بڑھ جائے گی، لیکن میں اپنے آپ میں جرأت پیدا نہیں کرسکا۔ پروگرام کی اختتامی تقریب کے لیے میں نے رپورٹ تیار کی تھی۔ وہ میں نے ڈاکٹر صاحبؒ کو دکھائی، ڈاکٹر صاحبؒ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا لیکن مزہ تب آئے گا جب آپ زبانی تقریر کریں۔ میں ان کی یہ خواہش پوری نہ کرسکا۔
ایک موقع پر انہوں نے عربی میں اپنی پہلی تقریر کاقصہ بھی بیان کیا۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں ڈاکٹر معروف دوالیبی کی دعوت پر شام گیا۔ نماز جمعہ کے موقع پر انہوں نے مجھے خطبہ دینے کا حکم صادر کیا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عربی میں تقریر نہیں کی، اس لیے مشکل ہے۔ اس پر ڈاکٹر دوالیبی نے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ حافظ قرآن ہیں، بسم اللہ کرکے خطبہ شروع کردیں اور ایک دو فقروں کے بعد قرآن کی متعلقہ آیت کا حوالہ دیں۔میں نے اس فارمولے پر عمل کیا اور یوں میں نے عربی میں تقریر شروع کی۔
فجی میں قیام کے دوران ڈاکٹر غازی صاحبؒ کے ساتھ خوب گپ شپ ہوتی اور تقریباً ہر موضوع پر بات چیت ہوئی۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں، میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب! آپ غازی کیسے بنے، یہ آپ کا تخلص ہے یا کنیت؟ مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ بچپن کی ایک یادگار ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ بچوں کو عام طور پر اپنے نام کے ساتھ لاحقہ یا سابقہ لگانے کا شوق ہوتاہے۔ دوسرے بچوں کے طرح میرے دل میں بھی یہ شوق چرایا اور اپنا نام ابوالعلاء محمود احمد غازی لکھنے لگا۔ یہ نام میں ہر کتاب اور کاپی پر لکھتا تھا۔ ایک استاد نے ابوالعلاء کے لفظ کو میرے لیے چھیڑ بنایا۔ وہ جب بھی مجھے پکارتے تو’’ ابوالعلا ‘‘یا ’’ابوالعلاکے بچے‘‘ کہہ کر پکارتے ۔ میں بھی اس سے چڑتا چنانچہ ابوالعلاء لکھنا تو چھوڑ دیا، البتہ غازی میرے نام کا حصہ بن گیا جو اب تک چلاآرہا ہے۔
جب میں نے ایم فل اقبالیات میں داخلہ لیا، تب بھی ڈاکٹر صاحبؒ سے ملاقات ہوتی تھی۔ ان کا پہلا سوال یہی ہوا کرتا تھا کہ ہاں بھئی، کیا بنا آپ کے مقالے کا؟ اور میرے پاس اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ ہوتا ۔ میرے لیے بار بار اس سوال کا سامنا کرنا مشکل تھا، اس لیے ایک طویل عرصے تک میں ان کے پاس نہیں گیا اور پھر تب گیا جب میں نے مکمل کرلیا۔
ڈاکٹر صاحبؒ کو جب میں نے مقالہ مکمل کرنے کی نوید سنائی توانہوں نے نہایت خوشی کااظہار کیا اور کہا کہ پی ایچ ڈی کی تیاری پکڑو، چنانچہ میں نے پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کروائی۔ غازی صاحب ہی میرے نگران تھے، ان کو میں نے مجوزہ مقالے کا خاکہ دکھایا۔ معمولی رد و بدل کے ساتھ انہوں نے مقالہ واپس دیتے ہوئے کہا کہ کہ جلدی جلدی پہلا باب لکھو تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، لیکن اس وقت میرے ساتھ جوسانحہ رونما ہوا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی خواہش پر میرا تبادلہ دعوۃ اکیڈمی سے یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات میں کردیاگیا۔ میں نے کہا کہ شعبہ امتحانات کی ذمہ داریوں کے ساتھ میں یہ ٹیڑھی کھیر کیسے کھاؤں گا؟ کہنے لگے میں نے بھی تو ان تمام مصروفیات کے باوجود پی ایچ ڈی کی تھی، لیکن غازی تو کوئی کوئی ہوتاہے،’’ حیرانوں‘‘ سے ’’غازی‘‘بننے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اب ان کی مصروفیات بھی کافی بڑھ گئی تھیں، اس لیے ان کی طرف سے ایم فل کے مرحلے جیسا تقاضا نہیں ہوتا تھا چنانچہ میں سست پڑ گیا، البتہ ان کی طرف سے جب بھی کوئی نوٹ آتا تو اس میں وہ مجھے ڈاکٹر حیران خٹک لکھتے اور یوں مجھے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے۔
ڈاکٹر غازی صاحبؒ کے ساتھ میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں جو اب میرے لیے متاع حیات بن گئی ہیں۔ وہ ایک باکمال شخص تھے۔ ایک طرف اگر علم کی بلندیوں پر فائز تھے تو دوسری طرف اعلیٰ انسانی اخلا ق کا مرقع بھی تھے۔ انہوں نے حیاتِ مستعار کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھا اور ایسی بھرپور ،متحرک ،بامقصد اور مصروف زندگی گزاری جس کی مثال ملنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی ابدی قیام گاہ دائمی نور سے منور فرمائے۔
علم و تقویٰ کا پیکر
قاری خورشید احمد
ڈاکٹر محمود احمد غازی علم ومعرفت کی دنیا میں ہمہ جہت شخصیت تھے۔ اصحاب علم ودانش آپ کو ایک جید عالم دین، مفسر، سیرت نگار، مایہ ناز معلم، مصنف عربی، فارسی اور انگریزی زبان کے ماہر کی حیثیت سے جانتے ہیں اور یہ مبالغہ آرائی نہیں، حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب علم ومعرفت کے آسمان پر بدر منیر بن کے چمکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگوں علمی وعملی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی ان صلاحیتوں کے پس منظر میں ایک قوت کار فرماتھی جس کو قرآن کی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے اور جس میں جس قدر تقویٰ کا جوہر نمایاں ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے علم ومعرفت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ فرمان الٰہی ہے: وَاتَّقُوا اللّٰہَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللّٰہُ (۲:۲۸۲) ’’یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔‘‘
درج ذیل سطور میں ڈاکٹر صاحب کے تقویٰ کے چند واقعات سپرد قلم کیے جاتے ہیں۔
نماز کی پابندی:
قرآن عزیز میں متقین کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یُقِیْمُونَ الصَّلٰوۃَ (۲:۳) یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نماز باجماعت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ۱۹۸۵ء میں وزارت مذہبی امور، اسلام آباد کے زیر اہتمام کمیونٹی سنٹر اسلام آباد میں ایک نمائش ’’بسلسلہ کتب سیرت‘‘ کا انعقاد ہوا اور وطن عزیز کی بڑی بڑی لائبریریوں سے کتب سیرت کو نمائش میں رکھا گیا۔ یونیورسٹی کی جانب سے جو لوگ خدمت پر مامور تھے، ان میں چند حضرات کے علاوہ میں (راقم الحروف) اور ڈاکٹر غازی بھی شریک تھے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایسے مواقع پر بروقت نماز ادا کرنے کی پابندی نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا کہ کسی بھی نماز میں اپنی مصروفیات کے باوجود تاخیر نہیں کرتے تھے اور جب نماز ادا کرتے تو اس میں خشوع وخضوع کا خاص خیال رکھتے اور جونہی اذان ہوتی تو آپ کی توجہ مسجد اور نماز کی جانب مبذول ہو جاتی۔ یہ بہت بڑی سعادت اور کامیابی کی دلیل ہے۔
جس شب آپ کو دِل کا دورہ پڑا، اس رات کو بھی آپ نے نماز عشا باجماعت ادا کی۔ رات ڈیڑھ بجے جب سینے میں درد محسوس ہونے لگا تو آپ کے بھائی ڈاکٹر محمد الغزالی آپ کو ہسپتال لے گئے اور صبح تک علاج معالجہ کی غرض سے ہسپتال میں رہے۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو اپنے بھیجتے حمزہ غزالی سے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے۔ آپ کے فرمانبردار بھتیجے نے آپ کو چارپائی پر ہی وضو کروایا۔ اسی دوران اپنی اہلیہ سے کہا کہ: پاؤں کی ایڑھیاں صحیح طریقے سے دھوئیں۔ آپ نے چارپائی پر ہی صبح کی نماز ادا کی جو کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد جب درد دل بڑھنے لگا تو آپ کے بھائی نے کہا: مولانا تھانویؒ نے دِل کے درد کے لیے جو دعا لکھی ہے، آپ کو یاد ہے؟ فرمایا: وہی دعا پڑھ رہا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے:
وَأَلَّفَ بَیْْنَ قُلُوبِہِمْ، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِیْ الأَرْضِ جَمِیْعاً مَّا أَلَّفَتْ بَیْْنَ قُلُوبِہِمْ، وَلَکِنَّ اللٰہَ أَلَّفَ بَیْْنَہُمْ، إِنَّہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ (۸: ۶۳)
ڈاکٹر صاحب اس آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے چونکہ ساری عمر نماز اور وظائف کی ادائیگی میں بسر کی، موت بھی آئی تو نماز کے بعد اور آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے۔ سچ فرمایا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح زندگی گزاروگے، اسی طرح موت آئے گی اور جس طرح موت آئے گی، قیامت کو اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔
ڈاکٹر صاحب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ عرصہ پانچ سال تک فیصل مسجد کے خطیب رہے اور جنرل ضیاء الحق کی نماز جنازہ بھی آپ ہی نے پڑھائی اور مختلف اسلامی ممالک سے آنے والے نمائندوں اور ہزاروں پاکستانیوں نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔
قرآن مجید کی تلاوت:
آپ قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے یہاں تک کہ دوران سفر جب جہاز یا گاڑی میں بیٹھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ آپ کے بیگ میں ہمیشہ قرآن مجید کا نسخہ موجود ہوتا تھا۔ آپ کی قرآن سے وابستگی کے بارے میں آپ کی مایہ ناز کتاب ’’محاضرات قرآنی‘‘ واضح ثبوت ہے۔
محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
متقین کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی محبت کو اللہ کی محبت تصور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غازی اپنے اقوال، اعمال اور اخلاق میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا وآخرت کی کامیابی کا ذریعہ قرار دیتے تھے جس کا واضح ثبوت آپ کی دو کتابیں’’ محاضرات سیرت‘‘ اور ’’محاضرات حدیث‘‘ ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے ڈاکٹر صاحب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آپ کی دوسری تصانیف ’’محاضرات قرآن‘‘ اور ’’محاضرات فقہ‘‘ کی طرح یہ دو کتابیں بھی اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں اور بار بار طبع ہو رہی ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ اقدس میں بصورت نعت بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا جس کی تفصیل اور نعتیہ کلام فارسی زبان میں ماہنامہ ’’تعمیر افکار‘‘ کراچی کے شماروں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل کمال کا منبع اور ان کی نسبت کو ہی سب سے بڑا اعزاز اور کمال سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں ان کی ایک فارسی نعت کا شعر ملاحظہ ہو:
کمال کاملاں یک قطرۂ بحر کمالش است
شود از نسبت نامش کمال کاملاں پیدا
]کاملین کا کمال، ان کے بحر کمال کا بس ایک قطرہ ہے۔ ان کے نام کی نسبت سے ہی کمال پیدا ہو جاتا ہے۔[
آپ کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بین ثبوت یہ ہے کہ فتنہ قادیانیت کے سلسلہ میں جنوبی افریقہ کے دارالحکومت، ڈربن کی عدالت میں قادیانیوں پر ایک مقدمہ چل رہاتھا۔ آپ نے بہت کم وقت میں اپنے حافظے کی بنیاد پر ایسے ٹھوس علمی دلائل پیش کیے کہ وہاں کی عدالت قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج ماننے پر مجبور ہوگئی۔
حج کی ادائیگی:
ڈاکٹر صاحب مرحوم کو حرمین شریفین سے بے پناہ محبت تھی ۔ آپ نے متعدد عمرے اور نو حج ادا کیے۔ قارئین کرام یہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو بانی پاکستان اور مصور پاکستان سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے ایک حج قائداعظم محمد علی جناحؒ کی طرف سے اور ایک حج علامہ محمد اقبالؒ کی طرف سے ادا کیا اور میرے علم کے مطابق یہ شرف صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب ہی کو حاصل ہے۔
پابندئ اوقات:
۱۹۸۵ء کا واقعہ ہے کہ اسلام آباد کے ایک کالج میں مقابلہ حسن قرأت منعقد ہوا۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو جج مقرر کیا گیا۔ (یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب قرآن کے حافظ اور جید قاری بھی تھے۔) ہمارے ساتھ دو حضرات اور بھی تھے جن کے نام یاد نہیں آرہے۔ بہر حال تقریباً بارہ بجے ہم لوگ اپنے کام سے فارغ ہوگئے۔ مجھے اور غازی صاحب کو واپس دفتر آنا تھا، کیوں کہ ہم دفتر ہی کی طرف سے دفتر کے ٹائم میں گئے تھے۔ ہمارے دوسرے ساتھی دفتر آنے کی بجائے اپنے گھروں کو روانہ ہوگئے۔ ان کے اس عمل کو ڈاکٹر صاحب حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گویا زبان حال سے یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان کا یہ عمل تقویٰ کے منافی ہے اور ایک دو بار دوران تقریر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا بھی کہ ہمیں دفتری اوقات کی پابندی کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ فرمان الٰہی ہے: أَوْفُواْ بِالْعَہْدِ (۱۷:۳۴) اور وَیْْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ، الَّذِیْنَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ (۸۳:۱، ۲)۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں وعدہ کی پاسداری اور دفتری اوقات کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب اپنے گھر نہیں گئے، حالانکہ ان کا گھرکالج کے قریب تھا۔ آپ سیدھے دفتر آئے اور کام میں مشغول ہوگئے اور یوں آپ نے تقویٰ وپرہیز گاری کا ثبوت دیا۔
احترام رمضان:
ڈاکٹر صاحب مرحوم رمضان المبارک کا بہت احترام اور روزے کا پابندی سے اہتمام فرماتے اور ماہ رمضان میں گھر پر قرآن شریف سناتے تھے۔ ایک دفعہ ماہ رمضان میں، میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب! روزے کیسے جارہے ہیں؟ کہنے لگے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھے جارہے ہیں۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ منزل سنا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے: ’’مجھ جیسے نالائقوں کا کیا سنانا ہے‘‘ (یہ کہہ کر کچھ آب بدیدہ سے ہوگئے جو کہ ان کی رقت قلبی اور جذبہ ایمانی کی دلیل ہے۔) بس گزارہ ہو جاتا ہے، منزل تراویح میں سنا دیتا ہوں۔‘‘ اس واقعہ سے رمضان کے احترام، خشیت الٰہی اور رات کے قیام کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔
سرکاری املاک کی حفاظت:
ڈاکٹر صاحب دو سال یونیورسٹی کے صدر رہے۔ اس دوران آپ نے قابل تقلید کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ یونیورسٹی کے تمام ملازمین کو خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’ہمیں سرکاری املاک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ گاڑیاں ہوں یا فرنیچر، بجلی کا استعمال ہو یا ہیٹر، اسٹیشنری ہو یا ٹیلیفون، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔‘‘ اس ضمن میں آپ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا جو سرکاری وغیرسرکاری دفاتر وغیرہ میں کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔آپ نے کہا:
جب میں ادارہ تحقیقات اسلامی میں ملازم ہوا تو انھی دنوں ایک دوست نے مجھے اپنے دفتر میں دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میزبان نے ٹیبل کی دراز سے ٹائپنگ پیپر نکال کر ہاتھ صاف کیے اور دوسرے صاحب کو بھی دیے۔ میں نے پیپر سے ہاتھ صاف کرنے سے انکار کر دیا اور دل میں اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مجھے کوئی اہم منصب عطا کیا تو میں سرکاری املاک کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب جب جامعہ کے صدر بنے تو آپ نے اس عہد کو حرف بحرف پورا کر دکھایا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دفتری کام میں جو کاغذ استعمال ہوتے ہیں، عموماً ان کی دوسری جانب خالی ہوتی ہے۔ میں ان کاغذات کو ضائع کرنے کی بجائے ان کی دوسری جانب کو کام میں لاتا ہوں۔ انہی پر ڈکٹیشن دیتا ہوں، املا لکھواتا ہوں اور علمی مضامین بھی لکھتا ہوں۔
جامعہ کی صدارت کے دوران آپ شریعت کورٹ کے جج بھی تھے۔ اپنے فیصلے جن کاغذات پر لکھتے، ان کو دونوں جانب سے کام میں لاتے اور اسٹینوگرافر کے حوالے کرتے۔ علاوہ ازیں جامعہ اور شریعت کورٹ کی جانب سے موصول آرڈر، مکتوبات وغیرہ کا باقاعدہ ایک بنڈل بنایا ہواتھا جس کی دوسری جانب مضامین وغیرہ لکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ شاید میرا یہ عمل درست نہ ہو۔ اسی سوچ بچار میں تھا کہ ایک شب امام شافعیؒ کے حالات زندگی پڑھنے لگا تو معلوم ہوا کہ امام شافعیؒ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات کو ضائع کرنے کی بجائے ان کو کام میں لاتے تھے۔ بس مجھے اطمینان ہوگیا اور کاغذات کو ضائع ہونے سے بچالیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی دفتر سے اسٹیشنری ایشو نہیں کروائی۔ دفتری کام کے لیے عام طور پر آپ ذاتی اسٹیشنری استعمال میں لاتے تھے۔
گیس ضائع نہ کریں:
ڈاکٹر صاحب کے ایک شاگرد جو کہ اب خود بھی ماشاء اللہ ڈاکٹرہیں یعنی ڈاکٹر شیخ تنویر احمد (اسسٹنٹ پروفیسر، اسلامک یونیورسٹی) ایک دن ڈاکٹر صاحب کے تقویٰ کا ایک واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگے کہ:
’’ڈاکٹر غازی کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ نے کلاس روم میں سوئی گیس کے ہیٹر کا پائلٹ جلتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پائلٹ بند کر دیا جائے۔ یہ قومی ملکیت ہے اور گیس ضائع ہو رہی ہے۔ آپ خود اٹھے اور پائلٹ بند کر دیا۔‘‘
غصہ کی حالت میں وضو:
ڈاکٹر صاحب کے پی اے عابد علی (جو دفتری معاملات میں آپ کی معاونت کرتے) کا کہنا ہے کہ اگر کسی معاملے میں ڈاکٹر صاحب کو غصہ آجاتا تو جوابی کارروائی کرنے کی بجائے آپ فوراً وضو کرنے لگتے اور تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت میں بشاشت پلٹ آتی۔ علاوہ ازیں آپ دفتری اوقات میں بھی ہمیشہ باوضو رہتے اور اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا تو انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے۔
مکان کی ریکوزیشن اور ٹیلیفون کا استعمال:
قارئین کرام! آپ حیران ہوگے کہ جس دور میں یونیورسٹی کے ملازمین اپنے اپنے مکانوں کی ریکوزیشن کرواتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے مکان کی ریکوزیشن نہیں کروائی حالانکہ ان کے گریڈ کے اعتبار سے خطیر رقم بنتی تھی۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مکان ایک ہے اور اس میں، میں اور میرا بھائی دونوں رہ رہے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح گھر میں جو سرکاری ٹیلیفون تھا، اس کا بل اپنی جیب سے ادا کرتے اور دفتری ٹیلیفون کو صرف اور صرف سرکاری مقاصد کے لیے استعمال میں لاتے۔
یونیورسٹی کے صدر کی حیثیت سے آپ کو سرکاری طور پر یہ اجازت تھی کہ یونیورسٹی میں آنے والے سرکاری وفود اورمہمانوں کی چائے اور ریفریشمنٹ وغیرہ سے تواضع کریں، لیکن آپ ہمیشہ اس سے دور رہے اوریوں آپ نے مہمانوں کے بہانے یونیورسٹی کے مال کو ضائع ہونے سے بچائے رکھا۔ اگر کوئی غیر سرکاری مہمان یادوست آتا تو اپنی جیب سے اس کی خاطر تواضع کرتے۔
ان واقعات میں ہمارے لیے تقلید کا سامان ہے، خصوصاً اس دور میں جب کہ چہار جانب بددیانتی اور کرپشن کی مسموم ہوائیں چل رہی ہیں۔ اے کاش! اگر ہر ذمہ دار پاکستانی اور سرکاری عہدوں پر فائز لوگ اسی طرح تقویٰ اور دیانتداری کا ثبوت دیں جس طرح ڈاکٹر غازی مرحوم نے دیا ہے تو وطن عزیز سکون واطمینان کا گہوارہ بن جائے۔
عفوودرگذر:
تحمل وبردباری کو قرآن مجید نے نیک لوگوں کی صفت شمار کیا ہے، چنانچہ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد الٰہی ہے: وَالْکَاظِمِیْنَ الْغَیْْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ (۳:۱۳۴)۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے علما کی سوانح عمریاں عفو ودرگذر کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ قسام ازلی نے ڈاکٹر محمود احمد غازی کو بھی عفو ودرگذر کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد الغزالی کی زبانی چند واقعات سپرد قلم کیے جاتے ہیں۔
۱۔ڈاکٹر محمد الغزالی بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی جن دنوں دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، ایک دن میں کسی کام سے ان کے دفتر گیا۔ اسی دوران دعوۃ اکیڈمی کا ایک ملازم اپنی پروموشن کا کیس لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی فائل ملاحظہ کرنے کے بعد کہا: اس میں چند قانونی رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ فی الحال آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوسکتا۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب سن کر ملازم سیخ پا ہوگیا اور ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا: ایک گھنٹہ سے میں دماغ کھپا رہا ہوں۔ جب آپ مر جائیں گے تو پھر میری پروموشن ہوگی۔ اس طرح کے اور بھی کئی ترش وتلخ جملے مسلسل بولتا رہا اور ڈاکٹر صاحب سنجیدگی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ آپ نے نہ تو اس کو ڈانٹا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی۔
۲۔ایک دفعہ یونیورسٹی کے طلبہ نے ہڑتال کردی اور طلبہ کی دو گاڑیاں بھر کر ڈاکٹر صاحب کے گھر کے سامنے اکھٹے ہوگئے۔ تقریریں کرتے رہے اور مختلف انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ڈاکٹر صاحب کا دور ایک مثالی دور تھا، مگر طلبہ بسا اوقات کچھ ایسے مطالبات بھی کر بیٹھتے ہیں کہ اصول وضوابط کی روشنی میں ان کا پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے نہ تو پولیس کو مطلع کیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ ڈاکٹر صاحب کے صبروتحمل کا طلبہ پریہ اثر ہوا کہ طلبہ خود ہی ندامت کے ساتھ واپس چلے گئے۔
۳۔اسی طرح ایک مرتبہ طلبہ نے آپ کے دفتر کے سامنے نعرہ بازی شروع کر دی اور مطالبات منوانے کے لیے تقریریں کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب سارا دن اطمینان سے کام کرتے رہے اورطلبہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ آپ کو متعدد بار ایسے مراحل اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لے کر مخالفین کو اپنا ہم نوا اور تابع فرماں بنا دیا اور کسی کے ستم کو ستم اور جفا کو جفا نہیں سمجھا اور یوں کہتے ہوئے ٹال گئے:
ستم کو ہم کرم سمجھے جفا کو ہم وفا سمجھے
جو اس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اس بت کو خدا سمجھے
اہل وعیال سے شفقت:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سب سے اچھا اور نیک وہ ہے جو اپنے گھروالوں کے معاملے میں بہتر ہو۔ ڈاکٹر غازی صاحب نے اس فرمان نبوی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ ڈاکٹر محمد الغزالی نے آپ کی گھریلو زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اہل خانہ سے نہایت خندہ پیشانی سے پیش آتے اور کبھی بھی کسی معاملہ میں ناراضی یا غصہ کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بچوں سے بھی بہت پیار کرتے اور ادب واحترام سے کلام کرتے اور بے پناہ پیاروشفقت کا اظہار کرتے۔ آپ کی اس شفقت اور محبت نے آپ کے گھر کو امن وسکون کا گہوارہ بنادیا تھا۔
والدین کی خدمت:
خوش نصیب اور بلند بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے والد کی رضا میں اللہ کی رضا کو اور والدہ کے قدموں تلے جنت کو تلاش کیا۔ ڈاکٹر غازی صاحب بھی یہ سعادت پا گئے اور والدین کی قدم بوسی کر کے خدمت کے اصول بتاگئے اور اللہ کو اپنا بنا گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے تازیست والدین کی خدمت کی اور خوب دعائیں لیتے رہے۔ چند سال قبل آپ کے والد مرحوم جب اس دنیا سے رخصت ہوگئے تو اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ ہر روز دفتر آنے سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضری دیتے اور شام کو سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حال احوال دریافت کرتے اور جھولیاں بھر بھر کر دعائیں سمیٹتے۔ اگر کہیں سفر میں ہوتے تو والدہ کے حالات سے باقاعدہ باخبر رہتے۔ آپ کی والدہ کی دعائیں ہمیشہ آپ کے شامل حال رہیں اور زندگی کے کئی پر خطر مراحل خوش اسلوبی سے طے کر گئے۔آپ کی والدہ محترمہ تاحال بقید حیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے دو ماہ قبل اپنی والدہ کو وہیل چیئر پر بٹھا کر عمرہ کرایا۔ جن لوگوں نے حرمین شریفین کی زیارت کی ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی عمرہ رسیدہ کو وہیل چیئر پر بیٹھا کر حج کے مناسک یا عمرہ کے اعمال بجالانا کس قدر مشکل مرحلہ ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے خندہ پیشانی کے ساتھ یہ سعادت حاصل کر لی۔
استقامت:
ڈاکٹر صاحب کی خداداد صلاحیتوں کو بھانپ کر بہت سے لوگوں نے آپ کو خریدنا چاہا، مگر آپ نے ہر پیش کش کو ٹھکرادیا اور إِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰہُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (۴۱:۳۰) کا دامن اس مضبوطی سے تھام لیا کہ بادِ مخالف کے تندو تیز جھونکے آپ کے پائے استقامت کو متزلزل نہ کر سکے اور ’’قل اٰمنت باللّٰہ ثم استقم‘‘ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر کی ایک علمی تقریر سے جس کا عنوان ’’اسلام اور مغرب۔۔۔موجودہ صورتحال‘‘ ہے، ان کی استقامت کا ایک قابل تقلید واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے دوران تقریر میں کہا:
’’اکتوبر ۱۹۷۴ء میں ایک پروفیسر صاحب امریکہ سے تشریف لائے۔ وہ ایک مشہور امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے پاکستان کے مختلف اداروں کا دورہ کیا۔ وہ ادارہ تحقیقات اسلامی میں بھی آئے۔ میں اس زمانے میں ادارہ تحقیقات اسلامی میں کام کرتا تھا۔ نوجوان تھا، مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہو چکاتھا۔ عربی اچھی جانتا تھا، انگریزی سے بھی شدبد ہوگئی تھی۔ تھوڑی بہت فرنچ بھی میں نے سیکھ لی تھی۔ وہ پروفیسر صاحب بہت سے لوگوں سے ملے، مجھ سے بھی ملے۔ مجھ سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں الگ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ میں ان سے ملنے چلا گیا۔ دوران ملاقات انہوں نے کہا، میں تمہیں اسکالر شپ دینا چاہتا ہوں امریکہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے۔ تم امریکہ کی جس یونیورسٹی میں چاہو، میں تمہیں اسکالر شپ دے سکتا ہوں۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ہارورڈ صف اوّل کی یونیورسٹی ہے اور ایم آئی ٹی ہے اور پرسٹن ہے، تین یونیورسٹیوں کا بڑا چرچا تھا، اس لیے میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ہارورڈ میں داخلہ دلوادیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے: میں تمہیں ہارورڈ میں داخلہ دلوادوں گا۔ کام یہ ہوگا کہ تم ایک سال کے لیے امریکہ آؤ، ہارورڈ یونیورسٹی میں کورس ورک کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ تین مہینے میرے پاس کورس ورک کرو، پھر واپس پاکستان آجاؤ۔ انہوں نے جو نقد وظیفہ بتایا، وہ اتنا تھا جتنا اس وقت حکومت پاکستان کے سیکرٹری کو بھی تنخواہ نہیں ملتی تھی، کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بھی نہیں ملتی۔ پاکستان میں رہ کر یہ وظیفہ ملنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کام یہ ہوگا کہ پاکستان میں رہ کر یہ معلومات جمع کرو کہ پاکستان میں دینی مدارس کیا کام کرتے ہیں، کتنے دینی مدارس ہیں؟ کون کون علماے کرام ان کو چلارہے ہیں، وہ کیا کیا پڑھاتے ہیں، کیا ذہن بناتے ہیں؟ اور جو لوگ ان سے تیار ہوتے ہیں، وہ بعد میں کیا کام کرتے ہیں اور ان کا رویہ مغرب کے بارے میں کیسا ہوتا ہے؟ یہ ساری معلومات جمع کر کے آؤ، پھر میرے ساتھ بیٹھ کر اس کو مرتب کرو، اس کی بنیاد پر تمہیں ہارورڈ یونیورسٹی پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دے گی۔
سچی بات ہے، میں اللہ تعالیٰ کی تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت یہ لگا کہ یہ تو صاف صاف جاسوسی کا کام ہے۔ دوران گفتگو پروفیسر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ مصر کے لیے ہے، ایک بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے لیے ہے۔ اب یہ چار بڑے ملک جو آبادی کے لحاظ سے صف اوّل کے ممالک تھے، جہاں دینی تعلیم کا پرائیویٹ نظام بڑا غیر معمولی تھا، وہاں کے لیے یہ کیوں تحقیق ہورہی تھی؟ اس پر لاکھوں روپے کے یہ مصارف کیوں کرائے جارہے تھے؟ میں نے کوئی ذاتی عذر بیان کر کے معذرت کر لی کہ میں سردست امریکا نہیں جا سکتا، لیکن اِس وقت میں جب بھی اس نوعیت کے مختلف معاملات کو دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مغربی دنیا کم ازکم ۱۹۷۴ء سے اس نکتے پر سوچ رہی تھی کہ دنیائے اسلام میں دینی تعلیم کا مستقبل کیا ہے، ماضی کیا تھا اور حال کیا ہے؟ اب پچھلے آٹھ دس سال سے اس میں زیادہ شدت آگئی ہے۔‘‘ (تعمیر افکار، ج ۸، شمارہ ۱۰، اکتوبر ۲۰۰۷ء)
قارئین کرام! ڈاکٹر صاحب تو ایک علمی شخصیت تھے۔ یہ کام تو ایک طالب علم بھی کر سکتا تھا، مگر آپ نے فوراً اس پیشکش کو ٹھکرادیا جس کے لیے لوگ پاپٹر بیلتے اور ترستے ہیں۔
یہ اس دور کی بات ہے جب دینی مدارس کو ختم کرنے کی خفیہ پلاننگ ہورہی تھی اور غیروں نے مکین ومکان کو اجاڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ایمانی فراست اور دینی غیرت کی قوت سے اس آزمائش سے دامن بچا گئے۔ استقامت کی سعادت پاگئے اور قیامت کے دن علماء ربانی کے گروہ میں یہ کہنے کے مجاز ہوں گے کہ:
بار الٰہ: جب اپنوں نے غیروں سے آشنائی کرلی تھی، روح اور جسم دونوں مرہون ہو چکے تھے، جب غیروں نے مکان ومکین پر منظم حملہ کیا تھا، دل ودماغ دونوں مجروح ہو چکے تھے اور بادسموم کے جھونکے شمع نبوت کو بجھانے کے درپے تھے تو ایسے نازک وقت میں اگرہم سے اور کچھ نہ ہو سکا تو غیروں کی مخالفت مول لے کر ملبہ کی حفاظت کی اور سامنے سے کسی کو مینا وساغر اٹھانے نہیں دیا۔
علماء وصوفیاء کے علم وہنر کا امتحان کم ہوا مگر کردار کا امتحان ہر زمانے میں ہوتا رہا، لیکن اہل استقامت اس امتحان میں کامیابی سے ہم کنار ہوئے۔ ڈاکٹر غازی بھی انہی کامیاب اور صاحب استقامت لوگوں میں سے ایک ہیں جو اغیار کی پیشکش ٹھکراگئے، وفا کے اصول بتا گئے اور ’پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ‘ کا درس دیتے ہوئے یہ فرما گئے:
چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا
نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا
سفر آخرت کے اشارے:
ڈاکٹر صاحب کی وفات سے تقریباً ایک ماہ قبل میں (راقم الحروف) نے خواب دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک براؤن رنگ کی خوبصورت قالین پر بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ایک رحل رکھی ہے جس پر قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور اس کا ایک ایک ورق تقریباً چار چار فٹ چوڑا اور آٹھ آٹھ فٹ لمبا ہے۔ چہار جانب نور کا ہالہ بنا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب بہت مسرور ہو ر ہے ہیں۔ جب راقم الحروف نے ڈاکٹر صاحب سے یہ خواب بیان کیا تو چند لمحے سکوت کے بعد کہنے لگے: ’’بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں‘‘۔ غالباً ڈاکٹر صاحب کی خاموشی اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ آپ کی مساعی جمیلہ کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے اور سفر آخرت بہت قریب ہے۔
اسی طرح آپ کی وفات سے تقریباً چند دن قبل دارالعلوم اسلامیہ، لاہور میں ’’تربیت مدرسین‘‘ کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شریک تھے۔ سیمینار کے اختتام پر آپ نے مولانا مشرف علی تھانوی (جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی) سے کہا کہ ’’مولانا! میری نماز جنازہ آپ نے پڑھانی ہے‘‘۔ آپ کی یہ تمنا پوری ہوئی اور علم وتقویٰ کا یہ پیکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔
نمازی اور نماز گاہ:
گزشتہ صفحات میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو ایک متقی کی حیثیت سے ملاحظہ فرمایا۔ جہاں تک آپ کی علمی صلاحیتوں اور خدمات کا تعلق ہے، اہل علم سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ آپ کی ساری زندگی علوم اسلامیہ کے حصول، تدریس اور اشاعت میں گزری اور بقول علامہ اقبال مرحوم کے:
اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں
کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی
ڈاکٹر غازی کے لیل ونہار بھی اسی قیل وقال میں گزر گئے اور اچھے حال میں گزر گئے۔ آپ کی مساعی جمیلہ کو اللہ نے وہ شرف بخشا کہ عالمِ برزخ میں بھی اسی محبوب عمل میں مشغول کر دیا جو کہ آپ کے تابناک مستقبل کی دلیل ہے۔
اس ضمن میں ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صاحب (جو کہ علمی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں) کا ایک خواب نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے ڈاکٹر غازی کی وفات کے چند دن بعد دیکھا۔ اس خواب میں غازیؒ کے تلامذہ، احباب اور دیگر اہل علم کے لیے اطمینان وتسلی کا سامان ہے۔
ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات غازی صاحب کو خواب میں دیکھا اور آپ تیز تیز چل رہے ہیں۔ میں نے کہا! غازی صاحب! آپ تو فوت ہوگئے ہیں۔ بتائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو جلدی جلدی آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے کرم والا معاملہ فرمایا ہے اور وہاں ایک نماز گاہ میں میرا محاضرۃ (لیکچر) ہوتا ہے۔ میں جلدی جلدی اس لیے جارہا ہوں کہ دیر نہ ہو جائے۔ (راقم الحروف سے یہ خواب ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب، ریسرچ سکالر، IRIنے بیان کیا)۔
آخر میں ڈاکٹر صاحب کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔
علم والے علم کا دریا بہا کر چل دیے
واعظان قوم سوتوں کو جگا کر چل دیے
کچھ سخن ور تھے کہ سحر اپنا دکھا کر چل دیے
کچھ مسیحا تھے کہ مردوں کو جلا کر چل دیے
میری آخری ملاقات
ڈاکٹر محمد افتخار کھوکھر
رات ساڑھے دس بجے کے قریب اچانک فشارِ خون کی وجہ سے بایاں بازو سُن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کا تذکرہ گھر والوں سے کیا تو انہوں نے فوری طور پر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (PIMS) جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے جواب میں کہا کہ فشار خون کم کرنے والی دوا لے لیتا ہوں۔اُمید ہے جلدہی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن گھر والوں کا اصرار تھا کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اسپتال جاکر ایمر جنسی وارڈ میں چیک اَپ کروالیا جائے۔
رات ساڑھے گیارہ بجے PIMS کے ایمر جنسی وارڈ کے کمرہ نمبر۳ میں ابتدائی چیک اَپ کے لیے داخل ہوا تو وہاں ڈاکٹر محمد الغزالی نظر آئے۔ میں نے ڈاکٹر غزالی صاحب سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا کہ آپ اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں موجود ہیں، خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر غزالی صاحب نے یہ سن کر میری توجہ ایمرجنسی ڈاکٹر کی میز کے عقب میں موجود کرسی کی جانب دلائی، میں نے اس جانب دیکھا تو وہاں محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب موجود تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر غازی صاحب کو سلام کیا اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا: غازی صاحب خیریت توہے؟ غازی صاحب نے تکلیف بھرے انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ یہاں سینے میں درد ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دل کی تکلیف کی کیفیت ہے۔ ڈاکٹر غزالی صاحب ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو بار بار کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں، غازی صاحب کی طبیعت مزید خراب ہوتی جارہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر روایتی انداز میں دوسرے مریضوں میں الجھا ہو ا تھا۔ ڈاکٹر غزالی صاحب کے مسلسل اصرار پر بالآخر ڈاکٹر غازی صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔
اتنی دیر میں کمرے میں موجود دوسرے ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ پہلے ای سی جی کرواکے لاؤں۔ اس کے بعد مزید کاروائی ہو گی۔ میں ای سی جی کرواکے امراض قلب کے شعبہ انتہائی نگہداشت میں پہنچا تو وہاں کاؤنٹر کے قریب ڈاکٹر غزالی صاحب مضطرب حالت میں موجود تھے۔
ڈاکٹر غازی صاحب شعبہ انتہائی نگہداشت کے ایک کمرے میں منتقل ہو چکے تھے اور ڈاکٹر طبی امداد کے حوالے سے مصروف تھے۔ میں نے کاؤنٹر کے قریب موجود ایک ڈاکٹر کو اپنی ای سی جی رپورٹ دکھائی تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر میرے ساتھ ڈاکٹر غزالی صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ دل کے حوالے سے تشویش کی بات نہیں۔
ڈاکٹر غازی صاحب کے کمرے میں ان کی اہلیہ محترمہ بھی موجود تھیں، اس لیے وہاں جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ڈاکٹر غزالی صاحب کو تسلی دی کہ ان شاء اللہ غازی صاحب بہت جلد صحت یا ب ہو جائیں گے۔ ان دعائیہ کلمات کے بعد میں نے ڈاکٹر غزالی صاحب سے اجازت لی اور رات دوبجے واپس گھرپہنچا۔ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ غازی صاحب جلد صحت یاب ہو جائیں۔ نماز ظہر سے پہلے موبائل پر مجھے ایک ایس ایم ایس وصول ہوا۔ ایس ایم ایس پڑھا تو ناقابل یقین اطلاع تھی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ دوپہر دو بجے قبرستان ایچ ٹن میں ادا کی جائے گی۔ وہ عظیم ہستی جس سے میر ی چند گھنٹے پہلے PIMS کے شعبہ انتہائی نگہداشت میں ملاقات ہوئی تھی، وہ اس طرح اچانک ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اس موقع پر بے اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کا واقعہ یاد آگیا جس میں حضرت خضرؐ کے ساتھ ملاقات سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک نے ستایا تو خادم سے مچھلی طلب کی تو اس نے کہا کہ راستے میں جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا، وہاں اچانک اس کے ہاتھ سے پھسل کر مچھلی دریا میں چلی گئی تھی۔ مجھے بھی ایسے لگا کہ غازی صاحب بھی میرے سامنے اچانک ہمیشہ کی دنیا میں چلے گئے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی، طویل عرصہ دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ اس دوران ان کے بہت قریب رہنے، ان سے سیکھنے اور کام کرنے کا موقع ملا۔ ممکن ہے وہ اکیڈمی کے دوسرے رفقائے کار کے لیے ڈائریکٹر جنرل ہوں، مگر میں نے انہیں ہمیشہ شفیق و مشفق بڑے بھائی کی طرح محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر غازی صاحب نے دعوۃ اکیڈمی کے تحت ماہنامہ ’’ دعوۃ‘‘ کے اجرا کا پروگرام بنایا تو انہوں نے مجھ ناچیز کے ذمے لگایا کہ’’ دعوۃ‘‘کے اجرا سے پہلے وطن عزیز کی معروف دینی، علمی وادبی شخصیات سے رابطہ کرکے اُن سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے راقم الحروف نے ایک خط کا مسودہ تیار کیا اور ممتاز علمی وادبی شخصیات کی فہرست مرتب کرکے غازی صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ غازی صاحب نے خط کے مسودہ کو مناسب قرار دیا اور دینی علمی وادبی شخصیات والی فہرست پر بھی پسندیدگی کا اظہار کیا۔
دو روز بعد ، ڈاکٹر غازی صاحب، دعوۃ اکیڈمی کے تحت ہونے والے ایک ماہ کے بین الاقوامی تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے بیرون ملک روانہ ہوگئے۔اَب ایک صورت یہ تھی کہ سرکاری اور روایتی انداز میں غازی صاحب کی واپسی کا انتظار کیا جائے کہ وہ ایک ماہ بعد واپس وطن تشریف لائیں گے تو خط کمپوز کرواکے اس پر ان کے دستخط کروانے کے بعد ممتاز علمی وادبی شخصیات کو خط بھجوایا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس کام کو سرکاری کی بجائے دعوتی و ذاتی سمجھتے ہوئے اور غازی صاحب کو ڈی جی کی بجائے مشفق ومہربان بھائی سمجھتے ہوئے، خط کو کمپوز کروانے کے بعد کسی فائل میں موجود نوٹ پر اُن کے موجود ہ دستخطوں کی فوٹو سٹیٹ کرواکے ان کے خط کے نیچے لگا کر تمام خطوط کی فوٹو کاپی کروالی جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اگلے ہی روز خط کمپوز کرواکے خط کے نیچے ان کے فوٹو کاپی شدہ دستخط لگا کر پچاس ساٹھ خطوط تیار کرکے ممتاز علمی ادبی شخصیات کو روانہ کردیے۔دو تین ہفتے کے دوران ممتاز علمی وادبی شخصیات کی بہت بڑی تعداد نے مجوزہ ’’دعوۃ ‘‘ کے اجرا کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنے گراں قدرمشوروں اور تجاویز سے نوازا۔ میں نے ان تمام خطوط کو ایک فائل میں محفوظ کر لیا۔
ایک ماہ کے بین الاقوامی تربیتی پروگرام کے بعد جب ڈاکٹر غازی صاحب واپس وطن تشریف لائے تو میں نے ملاقات کے موقع پر ان کی خدمت میں مجوزہ پرچے ’’دعوۃ‘‘ کے حوالے سے ممتاز علمی وادبی شخصیات کے خطوط والی فائل پیش کی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ میری جانب سے باضابطہ طور پر تو خط ان شخصیات کو روانہ ہی نہیں کیے گئے تھے تو یہ کس طرح ممکن ہوا ہے؟ اس پر میں نے بتایا کہ کس طرح ان کے دستخطوں کی فوٹو کاپی کرکے خط ممتاز علمی وادبی شخصیات کو بھجوایا گیا جس کے نتیجے میں اتنے سارے خطوط وصول ہوئے۔ یہ سن کر ڈاکٹر غازی صاحب زیرلب مسکراکر رہ گئے۔ کیا کسی سرکاری ادارے میں معمولی درجے کا ملازم یہ تصور کرسکتا ہے کہ وہ ادارے کے سربراہ کے نام کا خط، اس کے علم میں لائے بغیر بھجوادے اور اس پر اس کا مواخذہ نہ کیا جائے؟ یقیناًڈاکٹر غازی صاحب کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے میری اس حرکت کو درگزر کردیا۔
دعوۃ اکیڈمی اسلام آباد آنے سے پہلے مجھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جامع مسجد پنجاب یو نیورسٹی لاہور اور چند دیگر مساجد میں اعتکاف کا موقع ملاتھا۔ اسلام آباد میں جب پہلی بار فیصل مسجد میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا تو راقم الحروف نے مسلسل تین سال فیصل مسجد میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ پہلے سال صرف ۶۵ لوگوں نے اعتکاف کیا، دوسرے سال ۱۱۵ لوگ معتکف ہوئے جبکہ تیسرے برس شبینہ کا سلسلہ فیصل مسجد میں شروع ہونے کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے اعتکاف کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ عوام الناس میں بالعموم اور نوجوانوں میں بالخصوص معتکف ہونے کا سلسلہ ہر سال بڑھتا جارہا ہے لیکن اعتکاف کے مسائل سے عدم واقفیت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کوچھوئی موئی بنا لیا ہے اور کچھ نے اس کو پکنک کا درجہ دے دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ افراط وتفریط سے بچتے ہوئے معتکف ہونے والوں کو قرآن وسنت کی روشنی میں رہنمائی مہیا کی جائے۔
اس مقصد کے لیے راقم الحروف نے تمام مکاتب فکر کی قدیم وجدید کتب اور دینی رسائل و جرائد میں شائع ہونے والے مضامین کا جائزہ لے کر اعتکاف کے مسائل پر مختصر کتاب کا مسودہ تیار کرکے ڈاکٹر غازی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ قابل اشاعت بھی ہے یا نہیں؟ محترم غازی صاحب نے مجھ ناچیز پر بے پناہ اعتماد کرتے ہوئے مسودے کے صفحہ اول پر اکیڈمی کے شعبہ مطبوعات کے انچارج کو لکھا کہ اس کی کتابت و طباعت کا اہتمام کیا جائے۔ میں نے اس موقع پر فوراً غازی صاحب سے گزارش کی کہ راقم الحروف کو علم فقہ پر دسترس حاصل نہیں، اس لیے مسودے کو کتابت وطباعت سے پہلے علم فقہ کے کسی ماہر سے نظرثانی کروالی جائے۔ میری تجویز پر یہ مسودہ اکیڈمی کے ممتاز اسکالر اور فقہی ماہر مولانا فضل ربی کو بھجوادیا گیا۔ انہوں نے کمال شفقت سے مسودے پر نظرثانی کردی تو اس کے بعد اسے شعبہ مطبوعات کے حوالے کیا گیا۔ الحمد للہ اب تک ’’ اعتکاف، فضائل ومسائل‘‘ کے پانچ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو جب حکومت پاکستان کی جانب سے وفاقی وزارت مذہبی امور پر فائز کیا گیا تو اُن دنوں وہ بین الاقوامی اسلامی یو نیورسٹی اسلام آباد کے نائب صدر (علمی) کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ انہی دنوں کسی کام کے حوالے سے ڈاکٹر غازی صاحب سے ملاقات کے لیے نائب صدر جامعہ کے کمرے میں جانے کا موقع ملا۔ اسی دوران انہوں نے یو نیورسٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر فنانس خورشید عالم صاحب کو بلوایا۔ خورشید عالم صاحب تشریف لائے تو ڈاکٹر غازی صاحب نے انہیں مخاطب کرکے کہا کہ انسان بنیادی طور پر لالچی واقع ہوا ہے۔ اب جبکہ میں وفاقی وزیر مذہبی امور بن چکا ہوں تو وفاقی وزیر کی تنخواہ، یو نیورسٹی کے نائب صدر (علمی) سے زیادہ ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میں وفاقی وزیر کی ذمہ داری پر فائز رہوں گا، روزانہ بعد دوپہر یونیورسٹی آکر نائب صدر جامعہ(علمی) کے طور پر اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کروں گا، لیکن اس دوران یو نیورسٹی سے نہ تو تنخواہ وصول کروں گا اور نہ دیگر مراعات سے استفادہ حاصل کروں گا۔ یقیناًیہ کام کوئی اعلیٰ درجے کا صاحب تقویٰ ہی کرسکتا ہے۔
برصغیر ہی نہیں، عالم اسلام کی ممتاز علمی وادبی شخصیت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے جب عالم اسلام کے اہل قلم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے رابطہ ادب الاسلامی العالمیہ قائم کی تو عالم اسلام کے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان چیپٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ پاکستان چیپٹرکے صدر پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر مقرر کیے گئے جبکہ اسلام آبادچیپٹر کے لیے ڈاکٹرمحمود احمد غازی کو ذمہ دار بنایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر غازی صاحب کی ایف سکس والی رہائش گاہ میں اسلام آباد اور راولپنڈی کی ممتاز علمی وادبی شخصیات کو جمع کیا گیا تاکہ کام کا نقشہ تیار کیا جاسکے۔ ممتاز علمی وادبی شخصیات کی موجود گی میں ڈاکٹر غازی صاحب نے مجھ ناچیزکو رابطہ ادب الاسلامی العالمیہ ، اسلام آباد شاخ کا سیکرٹری مقرر کیا۔ میرے مسلسل انکار کے باوجود انہوں نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کردی۔ اس کے بعد رابطہ کی اسلام آباد شاخ کے تحت مختلف دینی اور علمی موضوعات پر لیکچرز کی سیریز کا پرگرام بنایا گیا۔ لیکن اسی دوران رابطہ ادب الاسلامی العالمیہ پاکستان چیپٹرکے ذمہ داروں کی روایتی سستی کی وجہ سے لاہور کے علاوہ فیصل آباد اور اسلام آباد میں بھی کام کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔
بچوں کے لیے راقم الحروف کی اب تک تین درجن سے زیادہ کتب شائع ہو چکی ہیں۔ اپنی شائع شدہ کتب وقتاً فوقتاً محترم غازی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا رہتا تھا۔جب میری کتاب ’’اقبال کہانی‘‘ چھپ کر آئی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ نے اب تک میری کسی کتاب کے متعلق اپنی تحریری رائے سے آگاہ نہیں کیا ۔ اس لیے اقبال کہانی پر اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ اس پر انہوں نے حسب ذیل تاثرات سے نوازا۔
’’ڈاکٹر افتخار کھو کھر اور بچوں کا اسلامی، دینی اور ملّی ادب اب لازم وملزوم بنتے جارہے ہیں۔ کھو کھر صاحب نے گزشتہ دو عشروں کے دوران بچوں کے ادب پر اتنا کام کیا ہے کہ اب اُردو کی ’’ تاریخ ادبیات اطفال‘‘ میں ان کا ایک مقام بن چکا ہے۔ ہمارے ملک میں اور بہت سے شعبوں کے علاوہ یہ اہم شعبہ بھی ایک عرصہ تک بے توجہی کا شکار رہا۔ پورے ملک میں صرف سعیدِ ملت حکیم محمد سعید ، میرزا ادیب اور اشتیاق احمد کے علاوہ ہمدرد نونہال اور تعلیم وتربیت کے لکھنے والوں نے چالیس سال یہ اہم ذمہ داری نبھائی اور حق یہ ہے کہ حق ادا کردیا۔
افتخار کھو کھر اسی روایت کے امین ہیں۔ اُن کے ہاں حکیم محمد سعید جیسی مقصدیت، میرزا ادیب جیسا فنی اسلوب اور اشتیاق احمد جیسی آسان اور رواں زبان یکجا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں میں کھو کھر صاحب کی تحریریں دن بدن مقبول ہورہی ہیں۔ ان کی درجنوں تحریروں میں بہت سی انعام یافتہ کتب بھی شامل ہیں۔ بعض کتابوں کے ایک ایک درجن ایڈیشن نکل چکے ہیں جن سے ان کتابوں کی مقبولیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔
زیر نظر کتاب ’’ اقبال کہانی‘‘ ان شاہین صفت بچوں کے لیے لکھی گئی ہے جو اقبال کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عزم اور جذبہ رکھتے ہیں ۔کتاب کا انداز بیان بہت آسان اور اسلوب بچوں کی سطح کے مطابق ہے۔ مصنف نے علامہ اقبال کی زندگی کے تمام اہم واقعات کو مکالمہ کے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔
مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اقبالیات اطفال میں ایک اہم اور مفید اضافہ شمار ہو گی۔ میں جناب ڈاکٹر محمد افتخار کھوکھر کو اُن کی اِس مفید کاوش پر دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کم سن قارئین میں مقبولیت عطا فرمائے۔‘‘
محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جیسی بین الاقوامی سطح کی علمی وادبی شخصیت کی جانب سے مجھ ناچیز کے متعلق یہ تاثرات میرے لیے متاع زندگی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ محترم غازی صاحب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمائیں اور ہمیں دنیا کی طرح آخرت میں بھی نعمت بھری جنتوں میں ان کی رفاقت نصیب ہو۔ آمین
مرد خوش خصال و خوش خو
مولانا سید حمید الرحمن شاہ
مرگ وزیست اس عالم کون وفساد کا خاصہ ہے۔ یہاں جو ذی روح آتا ہے، وہ موت کا ذائقہ ضرور چکھتا ہے۔ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مرتبہ پا لے، کتنی رفعتوں اور بلندیوں کو چھولے، نجوم وکواکب پر کمندیں ڈال لے، آفتاب وماہتاب کو پامال کر لے، بروبحر کی پہنائیوں میں اتر جائے، خلاؤں وفضاؤں کی تنگنائیوں کو روند ڈالے، تاروں بھری راتوں میں کہکشاؤں کے نقرئی راستے اپنے تصرف میں لے لے اور ارض وسما کے طول وعرض کی حقیقتوں کو پا لے، مگر موت سے مفر ناممکن ہے۔ خالق ارض وفاطر سماء نے کائنات ارضی وسماوی کی تخلیق سے پہلے ہی انھیں فناکرنے کا فیصلہ اور وقت مقرر کر رکھا ہے۔ موت وحیات کا نظام اپنے قبضہ قدرت میں رکھا اور آنے جانے کو بالخصوص سنت بنی آدم کا حکم تکوینی قرار دیا۔ بابا چلاسی فرماتے ہیں:
بو علی سینا وافلاطوں کجا غائب شدند
انبیا را ہم ز دنیا انتقالے دیدہ ایم
مالدارانش چرا بر مال خود فخر ے کنند
مالدارانش چو ما اندر سوالے دیدہ ایم
مگر اشرف المخلوقات کی صفت سے متصف بعض انسان ایسے بھی ہوئے ہیں جو اپنی اجلی سیرت، بلند کردار اور عمل صالح کے باعث یہاں سے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، کیوں کہ وہ صرف آنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ایسے ہی آنے والوں میں ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ بھی تھے جو اگرچہ اب جسم کی مادی متحرک اور متکلم صورت میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی شوخیت ایک رنگ تک محدود نہ تھی، بلکہ کئی قزحی رنگوں کے حسین امتزاج نے انہیں ایک کہکشاں کی صورت دے دی تھی۔ وہ درس نظامی کے فارغ التحصل فاضل تھے۔ فقہ وقانون کے زبردست ماہر تھے۔ عصری علوم کے بلندپایہ عالم تھے۔ عمیق النظر دانشور تھے۔ مسلم الثبوت ماہر تعلیم تھے۔ محقق ومدقق اور فلسفی ومتکلم تھے۔ بالغ نظر منتظم اور صاحب بصیرت مفکر تھے۔ اعلیٰ پایے کے خطیب ومقرر تھے۔ عظیم المرتبت مصنف ومولف اور قادرالکلام مترجم تھے۔ درویش ومنکسرالمزاج اور تواضع پسند فقیر طبع تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عظیم انسان تھے۔ سراپائے انس والفت،پیکرپریم وپیار اور مجسمہ محبت ومودت۔
ان کے انگ انگ سے اخلاص وچاہت کے سوتے پھوٹتے تھے اور ہر بال وبن سے شفقت ورافت کے چشمے ابلتے تھے۔ اس ماہر ہفت زبان کی ذات میں کتنے دھنک رنگ جمع ہو گئے تھے اور ان سب رنگوں میں اعلیٰ وبرتر رنگ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ تھا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ آپ کا وجود باجود سرتاپا صبغۃ اللہ میں رنگا ہو اتھا۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے یاد کیے گئے ، کسی بھی عہدہ ومنصب پر فائز ہوئے ، کسی بھی مرتبہ ومقام تک رسائی حاصل کی، کسی بھی لقب وخطاب سے مخاطب کیے گئے، کسی بھی شرف وکمال سے پکارے گئے اور کسی بھی اعزاز وتمغہ سے نوازے گئے، کبھی بھی اپنی جون نہیں بدلی، کپڑوں سے باہر نہیں آئے، ہمیشہ صبغۃ اللہ کا چولا زیب تن رکھا اور اللہ کے رنگ کے دائرے میں ہی رہے۔ اسی کو وجہ پہچان بنایا، اسی کو زندگی کا مقصد وحید ٹھہرایا اور اسی پر نازاں رہے۔
شاید ایسی ہی طرح د ار شخصیات کے لیے ہشت پہلو کا لفظ وضع کیا گیا ہے اور ہشت پہلو اشخاص وافراد اپنے علم وفہم، بصیرت ونظر، جدوجہد، حسن کردار واعمال اور اعلیٰ اخلاق واخلاص کی وجہ سے مر کر بھی نسیاً منسیاً نہیں ہوتے بلکہ امر ہو کر تاریخ میں زندۂ جاوید رہتے ہیں۔ ایسے انسان ہی ابنائے آدم کی بھیڑ میں عند اللہ اشرف المخلوقات کہلائے اور کرہ ارض پر خلیفۃ اللہ کے لقب سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علوم قدیم وفنون جدید کے قران السعدین تھے اور ہنر کہن وعصری کے مجمع البحرین۔ ان کی ذات ستودہ صفات آثار ماضی وحال کے مابین ’’اعراف‘‘ کا درجہ رکھتی تھی۔ جب علما کے درمیان براجمان ہوتے تو عصر حاضر کے بہت بڑے دانشور واسکالر دکھائی دیتے تھے اور جب جدید تعلیم یافتہ طبقے کے مابین رونق افروز ہوتے تو طلبہ وعلما کے ترجمان اور مدارس ومکاتب کے پرزور حمایتی لگتے تھے۔
ان کی ظاہری وضع قطع یقیناًمسٹروں والی تھی اور بودوباش پروفیسروں والی، چال ڈھال ڈاکٹروں کی طرح تھی اور رہن سہن بیورو کریسیوں جیسا جو اکثر علمی تصلب سے تہی دامن ہوتے ہیں اور علم کی گہرائی وگیرائی سے یکسر خالی۔ محض کاغذی ڈگریوں کے بل بوتے پر پھوں پھاں کرتے ہیں اور پنجابی لہجے میں انگریزی کا تڑکہ لگا کر اردو بیچاری کا خانہ خراب کرتے ہیں۔ انہیں اپنی جہالت نما علمیت جتانے کا ہیضہ ہوتا ہے اور بات بات پر مغرب کی ترقی کے حوالے دینے کا ٹھرک۔ ان جہل مرکبوں کو مشرق کی کوئی چیز بھلی نہیں لگتی اور وطن عزیز کی کوئی خوبی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہ کورچشم اتنے احسان فراموش ونمک حرام ہوتے ہیں کہ ہمیشہ مشرق کا کھاتے ہیں، مگر زندگی بھر گن مغرب کے گاتے ہیں۔ ان کی آنکھ میں سور کا صرف ایک بال ہی نہیں، سارا سورا سمایا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مدارس ومکاتب دینیہ کی اجلی ومزکی فضا کے پروردہ طالبان وعلما کو اسی سور مائی نگاہ سے دیکھتے اور انہیں حقیر ورذیل گردانتے ہیں، مگرہمارے فاضل ممدوح اپنے تبحر علمی، وسعت مطالعہ، ذکاوت وذہانت، استحضار وقوت حافظہ، بصیرت وفراست، قدامت وجدیدیت کے امتزاج، مافی الضمیر کے فی البدیہ اظہار کی قدرت، اسلام دشمن قوتوں اور تحریکوں سے آگاہی، دین میں نت نئے پیدا ہونے والے فتنوں اور فتنہ پردازوں پر کڑی نظر، تعلیم وتدریس اور تحریر وتقریر میں یکساں مہارت اور حاضر جوابی کے لاجواب ملکہ جیسی صفات عالیہ کے باعث پروفیسر ہو کر بھی مادر پدر آزاد پروفیسروں سے لگا نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی روشن خیال ڈاکٹروں کے قبیلے کے لگتے تھے۔
قادر وکریم قدرت نے ان کے وجود مسعود میں جو اوصاف وکمالات کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے، ان کے حامل اس عہد قحط الرجال میں شاید ہی دکھائی دیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ بہت کم لوگ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب جید وپختہ کار حافظ اور بہترین مجود ومقری تھے ۔ تکلف وتصنع سے گریزاں ، غنا وسرتال سے محترز اور سادہ وفطرتی انداز ولہجے میں تلاوت وقراء ت کرتے تھے۔ ماہ مقدس میں باقاعدگی سے اپنی قیام گاہ پر ہی بصورت تراویح قرآن کریم سنانے کا اہتمام کرتے اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی فارغ اوقات میں اس کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے۔ بالخصوص حالت سفر میں لہو ولعب اور لایعنیات میں مشغول ہونے کے بجائے احسن الکتاب کتاب اللہ کی تلاوت میں ہی مصروف رہتے تھے۔ نیز ان کی ان گنت صفات عالیہ وکمالات عمدہ میں سے ایک اعلیٰ صفت وخوبی یہ بھی تھی کہ ہمیشہ باوضو رہتے اور کبھی اس سے سرد مہری وغفلت نہیں برتتے تھے۔
آں ممدوح اپنے تبحر علمی وتفوق عملی اور عمق وتنوع کے باوجود طبعاً متواضع ومنکسرا لمزاج تھے۔ تصنع وتکلف سے مبرا اور بناوٹ وظاہر داری سے سراسر پاک تھے۔ دسیوں اعلیٰ عہدوں پر متمکن رہے اور بیسیوں اہم مناصب پر رونق افروز کیے گئے، مگر وضع داری، رکھ رکھاؤ اور مروت کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا اور نہ ہی متانت ووقار کے دائرے سے کبھی باہر آئے۔ پرویزی دور میں وزارت مذہبی امور کا قلم دان انہیں سونپا گیا اور سچ یہ ہے کہ ملک عزیز کی تاریخ میں پہلی بار، اور شاید آخری بھی، حق بحقدار رسید کا مظاہرہ کیا گیا، ورنہ عموماً چنوں کے کھیت کی رکھوالی گدھوں، خربوزوں کے فصل کی نگرانی گیدڑوں او ر شکار کیے گئے جانوروں کی حفاظت گدھوں کو ہی سونپی گئی ہے اور نااہل لوگ ہی وزارت کی کرسی پر بطور آرائش وزیبائش سجائے گئے ہیں۔ الغرض، اسی اثنا میں آں مکرم کے والد محترم جناب حافظ محمد احمد فاروقی کا پشاور میں انتقال ہو گیا اورآپ ان کی تجہیز وتکفین اور جنازہ وتدفین میں شرکت کے لیے پشاور تشریف لے گئے تواپنی گاڑی وعملہ کے افراد کو گھر سے دور چھوڑ گئے او ر ہر قسم کے پروٹوکول سے بے نیاز ومستغنی پیدل چل کر اکیلے گھر پہنچے ۔
زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی
بہ آب ورنگ وخال وخط چہ حاجت روئے زیبا را
پھر جب جنازہ وتدفین ہو چکی اور لوگ دوپہر کو آرام وقیلولہ کرنے لگے تو یہ زاہد مرتاض وشب زندہ دار بھی مکان کے کسی کونے کھدرے میں سمٹ سمٹا کر زمین پر ہی دراز ہو گئے۔ چونکہ مکان تنگ وچھوٹا تھا، مہمانوں کی آمد وآورد تھی اور مرگ وموت کا محل وموقع بھی تھا، ایسے میں سکھ چین کہاں، تسکین وطمانیت کیسی اور آرام وراحت کیونکر! چند گھڑیاں ہی لیٹ پائے تھے کہ آواز آئی، حضرات! ایک ضرورت شدیدہ کے باعث کمرہ ہذا خالی کر دیجیے۔ اس صدائے رحیل پر لبیک کہتے ہوئے دیگر اشخاص وافراد کے ساتھ وزیر موصوف بھی اٹھ کھڑے ہوئے، دائیں بائیں نظر ڈالی مگر نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ جب کہیں سر سمانے کی جگہ دکھائی نہیں دی تو کسی کو بتائے بغیر چپکے سے نکلے او ر گھر کے قریب ہی ایک خرابہ نما اور خام وناپختہ مسجد، جس کے درودیوار مٹی گارے سے بنائے گئے تھے اور جو خس وخاشاک سے مسقف کی گئی تھی، اس میں محو استراحت وخواب ہوگئے۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے ان کے نام ٹیلی فون آیا اور افراد خانہ اس طرف متوجہ ہوئے، لیکن تلاش بسیار کے باوجود کہیں دستیاب نہیں ہوئے۔ اس پر فکرو تشویش ہوئی اور ہر پیر وجواں ومرد وزناں فکرمند وسرگرداں ہوئے کہ آخر ڈاکٹر صاحب گئے تو کہاں گئے۔ جب سب تھک ہار چکے تو کسی نے یونہی سوچا کہ لگے ہاتھوں مسجد میں بھی جھانک لیں۔ جیسے ہی اس میں جھانکا تو حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ آں موصوف کچی مسجد کے کچے صحن میں کچی دیوار کے زیر سایہ اپنے جوتے سر کے نیچے رکھے غم جاں سے بے پروا، غم جاناں سے بے نیاز اور غم جہاں سے بے فکر، بڑے پرسکون انداز میں سو رہے ہیں۔
چوآہنگ رفتن کند جان پاک
چہ بر تخت خفتن چہ بر روئے خاک
یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب موسم گرما کا جو بن تھا اور سایہ دیوار ہنوز مثل اول تک نہیں پہنچا تھا۔ پشاورشہر کی حدت وتمازت ویسے بھی بہت مشہور ہے۔ کوئی پنکھا تک موجود نہیں اور سایہ دیوار بھی ناکافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس قناعت شعار بندے نے اسی پر اکتفا وقناعت کر لی اور جب جگایا گیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہوئے اٹھے، گردسے اٹے کپڑے جھاڑے اور گھر آ گئے۔
ڈاکٹر صاحب کی سیرت کے سارے رنگ حسین، سارے پہلو خوبصورت اور سارے اطوار من موہ لینے والے تھے اور بالخصو ص آپ کے حسن کردار کایہ تابناک انداز ہم جیسے ناہنجاروں کے لیے یقیناًدرس موعظہ اور لائق تقلید وعمل ہے کہ موصوف اپنے والدین کے از حد تابع دار وفانبردار اور مبالغہ کی حد تک ان کے مطیع وخدمت گزار تھے۔ ان کے والدمکرم کے مزاج میں جلالیت اور طبیعت میں تندی وتیزی کا عنصر کچھ زیادہ ہی در آیاتھا کہ بات بات میں آتش جیولہ بن جاتے اورکسی رو رعایت کے بغیر کھری کھری سنایا کرتے تھے اور بسا اوقات تو دو نکتی سنائے بغیر بھی نہیں رہتے تھے، مگر حیف ہے ان کی برخورداری پر، آفرین ہے ان کے تحمل وبردباری پر اور شاباش ہے ان کی اطاعت شعاری پر کہ سب کچھ خندہ روئی ورخشندہ جبینی سے سنتے اور اف تک نہیں کرتے تھے۔
غالباً ان کی وزارت کے زمانہ میں آں محترم فیصل مسجد کے اندر معتکف ہوئے اور وزیر موصوف بنفس نفیس سحر وافطار کا سامان لے کر مسجد میںآتے، انہیں سحری کراتے اور لوگوں کے سامنے ان کی جلی کٹی سن کر مسکراتے رہتے تھے۔ اگر کوئی انہیں سمجھانا چاہتا تو ناراضگی کا اظہار کرتے اور فرماتے، یہ میرااور میرے بابا کا معاملہ ہے اور آپ اس معاملہ میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ گویا
میان عاشق ومعشوق رمزیست
کراماً کاتبیں را ہم خبر نیست
لاریب ، ڈاکٹر صاحب انتہا درجہ کے پار سا اور پرہیز گار انسان تھے اور دوسروں کے لیے تتبع وتقلید کی علامت ونشان۔ زندگی کی آخری سانس تک اعلیٰ عہدوں ومناصب پر فائز رہے، مگر زندگی بھر دفتری وسرکاری ذمہ داریوں کے دوران کبھی حکومتی مراعات سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا اور سرکاری خزانہ کو ایک حبہ تک کا نقصان نہیں پہنچایا۔ صرف مقررہ مشاہرہ پر ہی گزارا کرتے تھے اور ہمیشہ صابر وشاکر رہے۔
ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ذہانت فطانت عطا فرمائی تھی، بے حساب استحضار اور قوت حفظ کاجوہر بخشا تھا اورلامتناہی حاضر جوابی کی صلاحیت سے ہم کنار کیاتھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اور جس کسی نے ان سے ادق سے ادق موضوع پر گفتگو کی یا کسی عقدۂ لاینحل اور مسئلہ مشکل کے متعلق استفسار کیا، آپ نے فی البدیہ مسکت اور تسلی آمیز جواب سے اسے شاد کام کیااور سننے والوں نے یہی جانا کہ موصوف اسی موضوع کے ماہر اورمتخصص ہیں۔
آپ چونکہ معتدل مزاج اور معتدل شخصیت کے حامل اور مثبت سوچ وفکر رکھنے والے عالم تھے،اس لیے ہر طبقہ فکرکو مطمئن کرنے کا فن خوب جانتے تھے اور اپنی شیریں مقالی، حسن عمل اور اعلیٰ اخلاق وکردار نیز انداز تکلم، طرز استدلال وحسن بیان اور حاضر جوابی کا باعث جلد دوسروں کا من موہ لیتے تھے۔ ہمارے مزاج میں عموماً افراط وتفریط کا غلبہ ہے اور بے اعتدالی وغلوپسندی کی فراوانی اور ہم ہرمعاملے میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اورہر پہلو سے حدود کے دائرہ سے تجاو ز کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ دعوت وتبلیغ ہو یا جہاد وقتال ، سیاست وسیادت ہو یا شریعت وطریقت، مدح ومنقبت ہویاتردید وتنقید، ذکر وتذکیر ہو یا ریاضت وعبادت، اقتصاد ومعاش ہو یا مذاکرہ ومکالمہ، بحث ومناظرہ ہو یا رویت ہلال کا مسئلہ، ذرائع ابلاغ وسائنس کے جدید وسائل سے استفادہ کا معاملہ ہو یا فقہ وفتاویٰ کی طرف مراجعت کی نوعیت، ہر جگہ ومقام اور ہر شعبہ وطریق میں اونچ نیچ کے عفریت نے اپنے خونخوار پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کوئی تو اس حد تک تنگ نظر ہے کہ اپنی سوچ وفکر کی تنگنائیوں میں چند رسومات جاہلانہ کو ہی شریعت سمجھتا اور مسائل فرقہ وارانہ کو دین حق یقین کرتا ہے، ظاہری شکل وصورت کو متشرع بنانے کے مرض میں مبتلا ہو کر متشددانہ رویہ اپناتا ہے اور بزعم خویش اسے افضل الجہاد کا نام دیتا ہے اور کوئی مذہب کے معاملے میں اتنا وسیع الظرف ہے کہ ایمان وکفر، توحید وشرک اور اصل اور بدعت کا فرق بیان کرنے کو بھی فرقہ واریت کے اسم سے موسوم کرتا اور ادائیگی فرائض کو کار عبث خیال کرتا ہے۔ کوئی اس قدر انتہا پسند ہے کہ اپنے مخالفین کو ابوجہل وابولہب کے القاب سے نوازتا اور ابن ابی اور ابن سبا سے بھی بدترسمجھتا ہے۔ اس کے برعکس اپنے ہم مسلک وہم مشرب مشائخ کو بغدادی وجیلانی کا ہم پلہ یقین کرتا اور رازی وغزالی سے برتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ہم نے آں ممدوح کے دامن کو اس طرح کی کج فکری کے داغوں سے یکسر پاک ومنزہ ہی دیکھا ہے۔ تحریر ہو یا تقریر، خطبہ ہو یا خطاب، وعظ ہو یا مقالہ، ہمیشہ ’’خیر الامور اوسطہا‘‘ کے دامن کو تھامے رکھا اور کبھی سرمو اعتدال کی راہ سے نہیں ہٹے اور نہ زندگی کے کسی موت پر جادۂ حق سے صرف نظر کیا۔
آں موصوف نے مختلف موضوعات پر اردو، عربی اور انگلش وغیرہ مختلف زبانوں میں متعدد وقیع وعلمی اور تحقیقی کتابیں تالیف کیں اور ملکی وبین الاقوامی کا نفرنسوں میں ان گنت محققانہ مقالے پیش کیے جنہیں علم کی دنیا میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا، دانشوروں کی طرف سے سراہا گیا اور حکما ومحققین کی جانب سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ان مقالات میں سے سلسلہ ہاے محاضرات کو بالخصوص اپنی علمیت وجامعیت، تحقیق وتفحص اور وسعت معلومات کے اعتبار سے علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی ملی اور علم دوست علما وذی علم فضلا نے قدرو وقعت کی نظر سے دیکھا ۔ یہ محاضرات جو مختلف عنوانات وموضوعات کے حوالے سے مستورات کے مختلف اجتماعات میں مختصر اشاراتی نوٹس کی مدد سے پڑھے جاتے رہے ہیں، بعد میں زیور طبع سے آراستہ ہو کر سات ضخیم جلدوں میں اشاعت پذیر ہوئے اور ہر جلد میں ایسے بارہ مقالے جمع کیے گئے جو متعلقہ موضوعات پر نادروعجیب معلومات کا بے بہا ومنفرد مجموعہ ہیں۔
محاضرات کے اولین مجموعہ کو محاضرات قرآن، ثانی کو محاضرات حدیث، ثالث کو محاضرات سیرت، رابع کو محاضرات فقہ، خامس کو محاضرات شریعت، سادس کو محاضرات معیشت اور سابع کو محاضرات سیر بین الاقوام کے خوبصورت ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور مایہ ناز تخلیق ’’تعلیمات قرآن علامہ اقبال کی نظر میں‘‘ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی صاحبزادیوں کو محض حافظہ ویادداشت کی بنیاد پر زبانی املا کروائی تھی۔ گوظاہر میں یہ مختصر لگتی ہے، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے انتہائی جامع وعلمی کتاب ہے جس کے مطالعہ سے ڈاکٹرصاحب کی وسعت معلومات اور فکر ونظر کی ہمہ گیری کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے فکر وفلسفہ سے بھی کماحقہ آگاہی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ صرف یک در یا در کوزہ ہی نہیں، جمیع ابحار ویموم کو کوزہ میں جمع کیا گیا ہے۔
ان کی آخری تصنیف غالباً ’’تاریخ الحرکۃ المجددیہ‘‘ہے جسے قطر میں قیام کے دوران عربی زبان میں احاطہ تحریر میں لایا گیا ہے اور کتاب کامحور ومرکز حضرت مجدد الف ثانیؒ کی شخصیت کو ٹھہرایا گیاہے۔ ان کے آثار واحوال اور تصنیفات وخدمات کا علمی جائزہ لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کے پچاس سے زائد منتخب مکتوبات کا فارسی سے عربی میں ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے جہاں ان کی فکری گہرائی ونظری گیرائی کی غمازی ہوتی ہے، وہاں عربی زبان کی اصالت وقادرالکلامی اور فارسی زبان کی گرفت وبندش کا پتا بھی چلتا ہے۔ عربی کی فصاحت وبلاغت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے عجمی نہیں، کوئی عربی نژاد وعربی النسل ادیب وسخن ور عربی زبان کے شہ پارے پیش کر رہا ہے اور فارسی کی عربی میں ترجمانی سے لگتا ہے ، کوئی فردوسی کا ہمزاد موشگافیاں کر رہا ہے۔
ڈاکٹر صاحب جہاں میدان تحریر وکتابت کے شہسوار تھے، وہاں تقریر وتبیان کی دنیا میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ دیگر خطبا ومقررین کے برعکس ان کے خطاب وتقریر کا انداز ہمیشہ منفرد ہوتا تھا۔ سرتال وغنائیت سے کلیتاً اجتناب کرتے تھے اور تمہید طولانی سے سراسر گریزاں ہوتے تھے۔ سادہ وصحیح لہجے میں مختصر حمد وثنا کے الفاظ دہراتے ،سنجیدگی ومتانت سے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کرتے اور اس کے بعد متعلقہ موضوع پر بولنا شروع کر دیتے اور پورے تسلسل و روانی سے بولتے ہی چلے جاتے تھے۔ ان کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دریا بپھرا ہو اہے اور اس کی موجیں اپنی طغیانی پر اٹھکیلیاں کر رہی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب گو بنیاد ی طور پر ایک فقیہ ومقنن اور حدود شرعیہ کے فاضل وقوانین اسلامی کے ماہر تھے، لیکن دیگر موضوعات میں بھی ان کے فکرکی رفعتیں اور شعور وآگہی کی وسعتیں کچھ کم نہ تھیں۔ علوم اسلامی کے جتنے شعبے اور فنون وہنر کے جتنے عنوان ہیں، اگر غو ر کیا جائے تو وہ سب ایک مسلک وحدت سے منسلک اور باہم ایک دوسرے مربوط ومنضبط کیے گئے ہیں اور یہ وحدت ویکجائی اور ارتباط وانضباط ہی انھیں دیگر علوم وفنون سے ممیز ونمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ کلام اللہ کو سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ وجدا کر کے دیکھنا ناممکن ہے، فقہ کو قرآن وسنت سے الگ کرکے سمجھنا ’’ کوہ کن وکوہ درپیش‘‘ کے مترادف ہے اور تاریخ وسیرت باہم لازم وملزوم ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن وسنت سے بھی جڑے ہوئے ہیں ۔یہی حال دیگر جملہ علوم وفنون کا ہے اور محترم ڈاکٹر صاحب کی ذات ستودہ صفات اس وحدت علوم اسلامی کی عملی وبین مثال ونظیر تھی۔ آپ تمام علوم اسلامیہ سے بہرہ ور تھے اور تمام فنون عصریہ سے واقف، آثار قدیمہ سے باخبر تھے اور روایات کہنہ سے آشنا، طریق جدید کی جدت کاریوں کے شناور تھے اور نئے فنون وہنر کی فتنہ سامانیوں وشرانگیزیوں سے ہوشیار۔ بعض علوم وفنون تلمیذاً حاصل کیے اور سبقاً پڑھے تھے اور بعض کثرت مطالعہ کی مرہون منت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر وتقریر سے قدامت وجدیدیت کے سب رنگ دھنکی رنگوں کی طرح ہم آہنگ اور غیر محسوس انداز میں جڑ ے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ۱۹۵۰ء کو حافظ محمد احمد فاروقی کے ہاں پیدا ہوئے جن کا علماء کاندھلہ کے اس مشہور علمی خاندان سے تعلق تھا جن میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا محمد علی کاندھلوی اور مولانا عبدالمالک کاندھلوی وغیرہ جیسے عظیم المرتبت ونابغہ روزگار رجال اعاظم گزرے ہیں۔ اس خاندان کی ارادت وبیعت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ سے تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے تعلیم کی ابتدا قرآن کریم سے کی اور اسے آٹھ برس کی عمر میں ازبر حفظ کر لیا ۔ اس کے بعد درس نظامی کی طرف متوجہ ہوئے اورابتدائی کتابیں کراچی کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں پڑھیں۔ متوسط کتب جامعہ اشرفیہ لاہور اور منتہی تعلیم القرآن راولپنڈی میں مکمل کیں۔ درس نظامی کی تکمیل کے بعد عصری علوم کی تحصیل کا شوق چرایا اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پہلے عربی میں ماسٹرز کیا اور پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آں ممدوح عالم اسلام کے ان معدودے خوش نصیب فضلا میں سے تھے جنھوں نے صرف سترہ برس کی عمر میں مسندتدریس کو رونق بخشی اور اسلامی علوم وفنون اور متداول وفنی کتب کی تدریس ان کا لازمہ حیات اور زندگی کا جزو لا ینفک رہی۔
راقم اثیم کی ڈاکٹر صاحب سے یاد اللہ اس وقت قائم ہوئی جب موصوف دعوہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل اور شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب لبیب تھے اور یہ تعلق وقت کے ساتھ ساتھ اکرام واحترام سے گزر کر تقدیس وعقیدت کے قالب میں ڈھل گیا ۔ اس شناسائی وآشنائی کی صورت وسبیل یہ بنی تھی کہ پروفیسر محمد امیرالدین مہر سربراہ تربیت ائمہ کورس، شعبہ دعوۃ اکیڈمی اسلام آباد ۱۹۸۸ء میں میرے سفر مقدس کے رفیق وساتھی رہے تھے۔ موصوف انتہا درجہ کے صاحب بر وتقویٰ، بلند پایہ عالم وفاضل اور بلا کی ذکی وذہین شخصیت تھے۔ فکر مودودی کے دلدادہ وشیدا تھے اور سید مودودی مرحوم کی تفسیر ’’تفہیم القرآن‘‘ کو سندھی زبان میں انہوں نے منتقل کیا تھا اور دیگر کتب کثیرہ بھی سندھی میں تالیف وتصنیف کی تھیں۔ پرانی وضع کے بزرگ تھے اور انتہا درجہ کے وضع دار وبامروت انسان تھے۔ یاروں کے یار اور ہمہ یاراں دوزخ وہمہ یاراں بہشت کا نظریہ رکھتے تھے۔ انتہائی خلیق وملنسار اور انتہائی مہمان نواز آدمی تھے۔ اکیڈمی میں جب بھی کوئی تقریب منعقد ہوتی ،موصوف مجھے ضرور یاد فرماتے اور ان کی وساطت سے حضرت ڈاکٹر صاحب کی زیارت ولقا کی سعادت بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ میں جب بھی اکیڈمی میں حاضر ہوتا، ڈاکٹر صاحب اعلیٰ ظرفی وبڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، گلے لگا کر جی آیاں نوں کہتے اور مصافحہ فرما کر احوال وخیریت دریافت کرتے تھے۔ جب بھی ملتے، یہ ضرور فرماتے کہ میں از اول تا آخر آپ کی نگری کا فرد، آپ کی برادری کا رکن اور آپ کے قبیلے کا ہی ممبر ہوں، اگرچہ حالات نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا ہے، تاہم میں کسی صورت بھی نہ تو کبھی اپنے قبیلے کو بھولا ہوں اور نہ ہی بھول سکوں گا، خواہ تحت الثریٰ میں رہوں یا بام ثریا پربسوں۔ بہرحال میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔
مجھے ہمیشہ ان کے مشاغل ومصروفیات اور سرکاری ذمہ داریوں کا احساس رہتا جس کے پیش نظر میں جلد اجازت لینے کی کوشش کرتا، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنی بے پایاں محبت وشفقت، بے حساب اخلاص مروت اور بے انتہا حقیر پروری وخوردنوازی کے تحت ’’ابھی آئے اور ابھی جانے کا ارادہ ہے‘‘ کہہ کر میری زبان بند کر دیتے تھے۔ پر تکلف خورونوش کا دور چلتا اور کتنی دیر تک بے تکلفانہ محفل جمی رہتی۔ علمی لطائف وحکایات کے تبادلے ہوتے،شائستہ وشستہ پھلجھڑیاں چھوڑی جاتیں اور مہذب وباوقار قہقہوں کا تبادلہ کیاجاتا تھا اور اس کے ساتھ مختلف مسائل وموضوعات بھی زیر بحث رہتے اور کئی لا ینحل عصری عقدے بھی موضوع سخن بنتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ ہر محفل میں میر محفل وشمع محفل بلکہ جان محفل ومان محفل آپ ہی ہوتے تھے۔ جب محفل برخواست ہوتی تو آں روح محفل، اکیڈمی کی مطبوعہ کتب ہدیۃً عنایت کرتے اور اپنی نئی چھپنے والی تالیف یا تصنیف بھی عطا فرماتے تھے۔
جب ڈاکٹر صاحب پرویزی دور حکمرانی میں وفاقی وزیر مذہبی امور بنائے گئے تو کچھ عرصہ کے لیے میل ملاپ وسلسلہ جنبانی میں تعطل در آیا۔ دریں اثنا ان کا دو تین بار تحیہ وسلام بھی آیا اور یہ پیام بھی کہ آپ اسلام آباد میں آباد ہیں، مگر افسوس اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ہمیں یاد نہیں کیا ،کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں فرمایا۔ میں نے جواباً عرض کیا: شاہوں کے مقبروں سے الگ دفن کیجیو، مجھے گور غریباں پسند ہے۔ مخدومی! آپ ایک ایسے خبیث الفطرت وغلیظ النفس شخص کی کابینہ کے رکن رکین ہیں جس کے نام سے ہی مجھے طبعاً نفرت اور اس ذات کے تصور سے گھن آتی ہے۔ ساحر لدھیانوی مرحوم نے کہا تھا:
تاج تیرے لیے اک مظہر الفت ہی سہی
تجھ کو اس وادئ رنگیں سے عقیدت ہی سہی
میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے
بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا معنی
ڈاکٹر صاحب کو معلوم تھا کہ میرا حضرت ڈاکٹر محمد حسین للٰہی مرحوم سے خصوصی تعلق ہے۔ بنا بریں انھوں نے حضرت للٰہی مرحوم ومغفور سے رابطہ فرما کر میری روش اور طرز فکر کے متعلق شکوہ کیا اور کہا کہ حضرت! حمید الرحمن سے فرما دیجیے، جس شخص کے نام اور کردار سے آپ کو نفرت ہے، مجھے بھی اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کراہت ہے۔ میں محض یہ سوچ کر اس بد بخت کی کابینہ میں شامل ہوا تھا کہ شاید کوئی اصلاح وصلاح اور ہدایت وراستی کا پہلو نکل آئے، مگر یہ میری بھول اور میری زندگی کی بھیانک خطا تھی۔ میں نے جب قریب ہو کر دیکھا تو اسے سراپا رجس ونجس بلکہ غلاظت وگندگی اور مجسمہ رذالت وضلالت پایا۔ اب میں نے اس خسیس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عملاً تو کب کا فارغ ہو چکا ہوں، صرف رسمی وکاغذی کارروائی باقی ہے۔ آپ جلد ذرائع ابلاغ سے میرے مستعفی ہونے کی خبر سن لیں گے اور یہ بھی کہ میں حکومت قطر کی دعوت پر قطر چلا جاؤں گا۔
حضرت للٰہی ؒ نے مجھے اس ساری صورت حال سے آگاہ کیا اور فرمایا: اب ان کی طرف سے دل میں کسی قسم کا کوئی تکدر اور میل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، حضرت میری سوچ وفکر کا مرکز ومحور صرف الحب للہ والبغض للہ ہے۔ اگر انھیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میرا دل بھی صاف ہے۔ حضرت للٰہی نے انھیں اس بات سے مطلع کیا اور ساتھ میرا رابطہ نمبر بھی دے دیا۔ چند دن بعد یہ خبر خوش کن سامعہ نواز ہوئی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے وزارت مذہبی امور سے استعفا دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہاتف کی یہ غیبی آواز بھی کانوں میں گونجی: میں محمود احمد غازی بول رہا ہوں، آپ سے ملنے کی خواہش ہے۔ کیا یہ خواہش یونہی ناتمام رہے گی؟ میں نے عرض کیا: حمید سر کے بل حاضر ہوا چاہتا ہے۔ اب میرے من کی خلش بھی ویسی ہی ہوگئی ہے جیسی آپ کے جی کی بے قراری ظاہر کرتی ہے۔
الفت کا جب مزا ہے کہ ہوں وہ بھی بیقرار
دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی
ڈاکٹر صاحب کی صحت آخر وقت تک لائق رشک تھی اور تندرستی قابل حسرت۔ انہیں جس نے بھی دیکھا اور جب بھی دیکھا، یہی جانا کہ آں موصوف سدابہار جوان رعنا ہیں۔ نہ کسی روگ ظاہری کے اسیر تھے اور نہ ہی کسی مرض باطنی میں مبتلا، مگر موت کا وقت مقرر ہے۔ جب جس کی اجل مسمی آ جاتی ہے اور وقت مقرر پورا ہوجاتا ہے تو وہ کسی کے ٹالنے سے نہیں ٹلتا۔ جو ہونا ہوتا ہے، وہ ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے۔ مجال نہیں کہ اس میں ایک لمحے کی تقدیم یا تاخیر ہو جائے۔ اللہ کے فیصلے میں بلاوے کا وقت آ گیا اور وہ خراماں خراماں اپنے بلاوے پر لبیک وسعدیک کہتے ہوئے سوئے اعلیٰ علیین چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جوار میں جگہ نصیب ہو، درجات بلند ہوں اور سیئات سے عفو ودرگزر کا معاملہ فرمایاجائے، آمین۔
ایک اک کر کے ستاروں کی طرح ڈوب گئے
ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے
اب جب کہ ان کا چاندی جیسا اجلا روپ اور سونے جیسا سنہری سروپ ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، صرف حسرت بھری یادیں او ر فکر بھری باتیں سوہانِ روح بن کر باقی رہ گئی ہیں، ایسے میں ان کے روپ وسروپ اور چہرے مہرے کے ان مٹ نقوش جو لوح خاطر پر ثبت وکندہ ہیں، انہیں برنگ پیرہن کاغذی، احرف والفاظ کے قالب میں ڈھال کر تصویری خاکہ کی صورت میں طشت ازبام وہویدا کر رہا ہوں، کیوں کہ
آج نظر کے سامنے حسن ہوا جو بے نقاب
دیکھ لیا قریب سے رنگ طلوع آفتاب
رخصت دوست کا سماں یوں نظر میں ہے کہ جوں
پھیل رہی ہو تیرگی ڈوب رہا ہو آفتاب
معتدل ومائل بہ طوالت قامہ، گٹھا ہوا وگداز جسم، نہایت متناسب اعضا وجوارح، گندمی ومائل بہ ملاحت رنگت، تیکھے ودلکش متین نقش، فراخ وچوڑا ماتھا، اس پر قسام ازل کی حسن قسمت کا چند رکھا، جھیل جیسی گہرائی وگیرائی کی غماز آنکھیں، بھرے ہوئے خم دار وکشادہ ابرو، پرکشش وپر گوشت ماکھڑا، رس بھرے رسیلے شفتین، ستواں و شہابی ناک، صدف فم وغنچہ دہن، مسٹرانہ وغیر مسنون داڑھی، کبھی شلوار وقمیص اور قراقلی ٹوپی زیب تن اور کبھی انگریزی سوٹ بوٹ سے آراستہ بدن۔ افسوس جن کی زندگی ماہتاب سے تابندہ وتابناک تھی، وہ اپنی زندگی کی ساٹھ بہاریں دیکھ کر اس دنیاے دوں سے رخصت ہو گئے۔
کھوئیں گے ہمیں لوگ تو پھر پانہ سکیں گے
یوں جائیں گے دنیا سے کبھی آ نہ سکیں گے
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ کچھ یادیں، کچھ باتیں
ڈاکٹر محمد امین
ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی راہئ ملک عدم ہوئے اور اتنے اچانک کہ ابھی تک یقین نہیں آتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ غالباً ۱۹۹۳ء کی بات ہے، جب ہم مرحوم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کے ساتھ ایک نیم سرکاری تعلیمی فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹرنصابیات کے طور پر کام کرتے تھے۔ہم نے اڑھائی تین سال کی محنت سے پہلی سے بارہویں تک کے نصاب کو از سر نو اسلامی تناظر میں مدون کیا۔ اب اس نصاب کے مطابق نصابی کتب مدون کرنے کا مرحلہ درپیش تھا، لیکن ٹرسٹیوں اور ملک صاحب میں اختلافات کے پیش نظر کام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ہم نے چند ماہ انتظار کیا، لیکن جب دیکھاکہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا تو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ’’ادارہ تحقیقات اسلامی‘‘ کے سربراہ اور اپنے مہربان ڈاکٹر ظفر اسحق انصاری صاحب سے اس کا ذکر کیا کہ کسی دوسری مصروفیت کا متلاشی ہوں۔
چند دن بعد ان کا فون آگیا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب سے آکر ملو۔ وہ ان دنوں ڈائریکٹر جنرل دعوۃ اکیڈیمی تھے۔ میں جا کر ان سے ملا۔ سانولا رنگ، لمبا قد اور لباس میں قدیم و جدید کا امتزاج یعنی سوٹ کے ساتھ نکٹائی لیکن سر پہ جناح کیپ اور چھوٹی داڑھی۔ خندہ پیشانی سے پیش آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کی زیادہ تردلچسپی اسلامیات کے کن شعبوں سے ہے؟ میں نے کہا: ’’مزاجاً دعوت سے، لیکن تعلیمی اسناد کے لحاظ سے اسلامی قانون سے‘‘۔ کہنے لگے خیر، ان شاء اللہ دونوں اپنے بس میں ہیں۔ (وہ ان دنوں شریعہ اکیڈیمی کے انچارج بھی تھے)۔ چنانچہ انہوں نے میری تعیناتی شریعہ اکیڈیمی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کرا دی۔ وہاں سول اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججوں کی اسلامی قانون میں تربیت کے علاوہ شریعہ میں تالیف و تدوین کا شعبہ بھی میرے سپرد تھا۔ وہ ان شعبوں میں میری تجاویز اور رپورٹوں پر عموماً من و عن صاد کر دیتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر میں نے نوٹ لکھا کہ مجھے ان کاموں کا کوئی تجربہ نہیں اور یہاں کوئی ایسے ساتھی بھی نہیں جن سے مشاورت کی جاسکے اور یہ بڑے بڑے علمی منصوبے ہیں اور آپ بلابحث و ادنیٰ تغیر ان پر صادکردیتے ہیں۔ جواب میں ’’من تواضع للہ رفعہ‘‘ کا مختصر جواب لکھ کر یہ باب بند کردیا۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ان کی علمی ترقی پر خوش ہوتے تھے۔
ان دنوں میری فیملی لاہور میں تھی، لہٰذا میرے پاس کافی وقت بچ جاتا اور میں نے نوائے وقت میں ہفتہ وار کالم ’’فکر و نظر‘‘ لکھنا شروع کردیا۔ ایک دفعہ میں مساجد میں اسلامی تعلیم کے موضوع پر کالم لکھنا چاہتا تھاتو میں نے بعض معلومات کے لیے ایک جاننے والے صاحب کو وفاقی وزارت تعلیم میں فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک سروے کرایا تھا جس سے پتہ چلا کہ ہماری مساجد میں سے صرف ۲۵ فیصدایسی ہیں جہاں باقاعدہ سند یافتہ امام ہیں جو عوام کو قرآن و حدیث کا درس دے سکتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار چونکا دینے والے تھے۔ اتفاق سے اسی شام کسی وجہ سے مجھے ڈاکٹر غازی صاحب کے گھر جانا پڑا۔میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اپنے کالم کے سلسلے میں یہ اعداد و شمار ملے ہیں۔کہنے لگے، اس بات کو ہرگز اپنے کالم میں نہ لکھنا کیونکہ اس سے علما کی ہوا خیزی ہوگی اور علما چونکہ ہمارے معاشرے میں دین کے نمائندے ہیں، لہٰذا اس سے دین کی بھی ہوا خیزی ہوگی۔
اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک سالہ قیام کے دوران ہی مجھے یہ آئیڈیا سوجھا کہ اسلامی مشاورتی کونسل چونکہ غیر فعال ہے، لہٰذاکیوں نہ پرائیویٹ سطح پر مختلف مسالک کے علماے کرام اور اسلامی سکالرز پر مشتمل ایک علمی مجلس ایسی بنائی جائے جو معاشرے کو درپیش مسائل میں اسلامی حوالے سے غور کرکے اپنی سفارشات عوام اور حکومت کے سامنے لائے تاکہ اگر وہ چاہیں تو اس سے استفادہ کرلیں۔ میں یونیورسٹی میں نیا اور ناتجربہ کار تھا اورغازی صاحب کا جونیئرتھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس معاملے میں میری بھرپور حوصلہ افزائی کی اوراس منصوبے کو آگے بڑھانے میں میرے ساتھ مل کر کام کیا۔ مجوزہ ادارے کی تشکیل کے لیے بلائے گئے ہر اجلاس میں پرجوش طریقے سے شریک ہوتے بلکہ بہاول پور یونیورسٹی سے آئے ہوئے اپنے برادر نسبتی ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لاتے۔(اس معاملے میں معروف اہل حدیث عالم مولانا عبدالغفار حسن مرحوم نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا) لیکن برا ہو ’’معاصرت‘‘ کا کہ یونیورسٹی کی ایک سینئر اسلامی شخصیت نے اس کام میں اس طرح مداخلت کی کہ اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ ان کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی۔ (ہماری اس دیرینہ خواہش کی مظہر ’’مجلس فکر و نظر‘‘ تھی جو ہم نے جامعہ پنجاب کے دوران قیام تشکیل دی اور اب ’ملی مجلس شرعی‘ہے جوسارے دینی مکاتب فکر کے علماے کرام کا متحدہ پلیٹ فارم ہے)۔
غازی صاحب مرحوم کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ دینی فکر و عمل میں معتدل مزاج تھے۔ نہ تجمدکے قائل تھے اور نہ تجدد کے۔ یوں ہمارے معاشرے میں جو اصحاب و طبقات تجمدکی طرف میلان رکھتے ہیں، وہ ان کے ناقد تھے اور جو اصحاب تجدد کی طرف میلان رکھتے ہیں، وہ بھی انہیں ناپسند کرتے تھے لیکن ہمارے نزدیک ان کا معتدل رویہ قابل تعریف تھابلکہ وہ جدید و قدیم کے امتزاج کا بہترین نمونہ تھے۔ کراچی یونیورسٹی میں ہمارے دوست خالد جامعی صاحب جو جدیدیت کے خلاف تیغ براں ہیں، وہ غازی صاحب کا شمار بھی تجدد زدہ لوگوں میں کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس کا اظہار اپنے جریدے ’’ساحل‘‘ میں کیااور غازی صاحب کے خلاف لکھنے کا ارادہ ظاہر کیاتو ہم نے دوستانہ اختلاف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ایسانہ کریں کیونکہ ہماری رائے میں غازی صاحب اس عتاب کے مستحق نہ تھے، چنانچہ انہوں نے وقتی طور پر ہماری درخواست قبول فرما لی۔ (گوجامعی صاحب اپنے نظریات میں بہت پختہ ہیں اور اپنی رائے پر اب بھی قائم ہیں)۔
ہمارے نزدیک فکری رویوں کے بڑے بڑے دائرے ہیں اور ہر دائرے کا ایک سنٹر ہوتا ہے اور جو لوگ اس سنٹر سے تھوڑا دائیں یا بائیں ہوتے ہیں، ان کا شماربھی اسی دائرے میں ہونا چاہیے، خواہ وہ اس دائرے کی مین اسٹریم سے تھوڑے دور اورمختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً متجد دین کے دائرے میں برصغیر کی دینی روایت کے لحاظ سے سرسید، چکڑالوی، امرتسری، غلام احمد پرویز،جاوید احمد غامدی صاحب وغیرہ ہیں لیکن اقبالؒ ، مولانا مودودیؒ اورڈاکٹرغازی صاحب کو اس دائرے میں شامل کرنا ہمارے نزدیک زیادتی ہے۔ ہماری غازی صاحب سے اس موضوع پر کئی دفعہ بات ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی اس طبقہ متجددین کے حق میں کلمۂ خیر نہیں کہا۔ مغرب کے حوالے سے جو ان کی اپروچ تھی، ضروری نہیں ہے اس سے خالد جامعی صاحب جیسے اصحاب بھی مطمئن ہوں، لیکن اس کے باوجود انہیں مغرب زدہ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح بلاشبہ وہ حلقہ دیوبند کے قریب تھے (بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خاندان میں سے تھے) لیکن ہمارے علم اور مشاہدے کی حد تک وہ اس میں بھی معتدل مزاج تھے اور ہرگز متشدد نہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بریلوی بھائیوں کو ان کا یہ اعتدال نہ بھاتا ہواور وہ انہیں حکومت میں ایک دیوبندی وزیر سمجھ کر ان کی مخالفت کرتے ہوں۔
وزارت سے یاد آیا کہ بعض لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں وزیر مذہبی امور کی ذمہ داری کیوں قبول کی؟ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، ہم لاہور میں تھے۔ ایک دفعہ کسی مظلوم کی مدد کے سلسلے میں ان کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے بھرپور معاونت کی، لیکن ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ حکومت میں خاصے غیر مطمئن تھے اور اپنے آپ کو misfit محسوس کرتے تھے اور اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اب انہیں کمبل نہیں چھوڑتا تھا۔ ناچار انہوں نے پبلک بیان دے دیا کہ وہ فلاں مہینے وزارت چھوڑ دیں گے اور پھر چھوڑ بھی دی۔ یار لوگ کہیں گے کہ قبول ہی کیوں کی تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ غازی صاحب اپنی اہلیت کے بل پر بڑے سے بڑے منصب کے اہل تھے، لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جو داڑھی رکھتا، ٹوپی پہنتااور عربی اسلامیات میں مہارت رکھتا ہو، اسے مولوی سمجھتا اور بطور مولوی ٹریٹ کرتا ہے (خواہ وہ روایتی ’مولویت‘ سے دور ہی کیوں نہ ہو)۔ اس طرح باصلاحیت لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے اظہار و استعمال کے موزوں مواقع میسر نہیں آتے اور ان میں ردعمل کی ایک نفسیات پیدا ہوجاتی ہے اور پھر جب انہیں کوئی موقع ملے تو وہ اسے قبول کرلیتے ہیں، خواہ اس کی ’’موزونیت‘‘ کچھ مشکوک ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے بھی معتدل مزاج ہونے کی وجہ سے غازی صاحب اپنی افتاد طبع میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی نہ تھے۔ پھر ملت کا درد رکھنے اور معاشرے کے دینی مستقبل کے حوالے سے سوچنے والے شخص کی حیثیت سے ان کے ذہن میں کئی منصوبے تھے۔ ان کا خیال ہوگا کہ وہ اقتدار میں آکر ان منصوبوں میں سے بعض پر عمل کرسکیں گے، لیکن غالباً حکومت میں جانے کے بعد جلد ہی انہیں اندازہ ہوگیا کہ ہمارا سیاسی نظام اور بیوروکریسی کا نظام نمک کی وہ کان ہے جس میں جانے والا خود نمک ہوجاتاہے اور اس کا اپنا میٹھا پانی بھی کھاری ہونے لگتا ہے، چہ جائیکہ وہ وہاں کے پانی کو میٹھا کرنے کے کسی منصوبے پر عمل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وزارت میں زیادہ دیر نہ ٹک سکے اور باہر آگئے۔ غازی صاحب کے وزارت قبول کرنے کے حوالے سے ہم نے جو کچھ ابھی کہا، وہ ہمارا ذاتی تجزیہ ہے جس سے اختلاف کا حق ہر صاحب فکر و نظر کو ہے۔
پھر ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر ہوگئے ہیں۔ یہ ان کی محبت اور بڑا پن تھا کہ انہوں نے خود فون کرکے مجھے کہا کہ میرے پاس اسلام آباد آجاؤ، یہاں کام کے بڑے مواقع ہیں اور ترقی کے بھی۔ ایک یونیورسٹی کے زیرک سربراہ کی حیثیت سے انہیں خوب اندازہ تھا کہ یونیورسٹی بڑی بڑی بلڈنگوں کانام نہیں ہوتی بلکہ جتنے بڑے اہل علم اس سے وابستہ ہوں، یہ اتنی ہی بڑی ہوتی ہے اور جب اس میں کام کرنے والے بونے ہوں تو یونیورسٹی کی عظیم الشان بلڈنگیں اسے عظمت نہیں بخش سکتیں۔ چنانچہ جب وہ یونیورسٹی کے صدر نہ رہے اور ان کا واسطہ بونوں سے پڑا تو وہ خاموشی سے یونیورسٹی چھوڑ گئے اور جامعہ قطر چلے گئے کیونکہ وہ لڑنے والے آدمی تھے ہی نہیں۔ ہاں! تو ہم عرض کر رہے تھے کہ غازی صاحب نے ہمیں اسلام آباد یونیورسٹی آنے کی دعوت دی، لیکن ہم وہ راجپوت ہیں جن کا راج نہیں رہا، لیکن بھوت باقی رہ گیا ہے چنانچہ ہم نے تحریک اصلاح تعلیم اور نئے رول ماڈل تعلیمی اداروں کے قیام کے محاذ سے نہ ہٹنے کی ضد میں ان سے معذرت کرلی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کوئی قلعہ فتح نہیں کرسکے، لیکن ہمارے نزدیک وفاداری بشرط استواری ہی اصل ایماں ہے۔ چنانچہ ہم اپنی ہٹ پہ قائم ہیں کہ غازی نہ بن سکے، شہید تو ہوں گے اور شہید بھی نہ ہوئے تو شہادت کی تمنا تو ہے۔ ہم معرکۂ کارزار میں تو ہیں، ہاتھ پاؤں تو چلا رہے ہیں __ اورممکن ہے ہمارے رب کو ہماری یہی ادا پسند آجائے۔
جب ہم نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی تو سرکاری ضرورت کے تحت ایک سال ہم نے جوغازی صاحب کے ساتھ اسلامی یونیورسٹی میں کام کیا تھا، اس کاتجربے کا سرٹیفکیٹ بھجوانے کی ان سے درخواست کی۔ انہوں نے سرکاری خط بھجوانے کے ساتھ جو ذاتی خط مجھے لکھا، وہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں مرجاؤں تو یہ خط میری قبر میں رکھ دینا کہ یہ ایک مسلمان کی دوسرے کے بارے میں بے ریا شہادت ہے۔ شاید اللہ اسے قبول فرمالے۔ اللھم اغفرلہ وادخلہ مدخلاً کریما وارزقہ جنۃ الفردوس۔ (بشکریہ ’البرہان‘ لاہور)
ایک بامقصد زندگی کا اختتام
خورشید احمد ندیم
ڈاکٹر محمود احمد غازی رخصت ہوئے۔ ایک با مقصد اور با معنی زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔ میری برسوں پر پھیلی یادیں اگر ایک جملے میں سمیٹ دی جا ئیں تو اس کا حاصل یہی جملہ ہے، لیکن غازی صاحب کے بارے میں ایک جملہ ایسا ہے کہ میں اس پر رشک کرتا ہوں۔ بہت سال ہو ئے جب غازی صاحب کے ایک دیرینہ رفیق نے ان کے بارے میں مجھ سے کہا: ’’میں نے علم اور تقویٰ کا ایسا امتزاج کم دیکھا ہے۔‘‘یہ بات کہنے والی شخصیت بھی ایسی ہے کہ میں ان کے علم اور تقویٰ دونوں پر بھروسہ کر تا ہوں۔ یہ گواہی وہ ہے جو یقیناًفرشتوں نے محفوظ کی ہوگی اوراللہ کے حضور میں ان شاء اللہ ان کی بلندئ درجات کا باعث بنے گی۔
غازی صاحب کے بارے میں ،میں یہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان کی جگہ لے سکے۔ غازی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جوقدیم اور جدید کا ایک امتزاج تھے، تاہم ان کا جھکاؤقدیم کی طرف رہتا تھا۔ یہ ان کی احتیاط کا اظہار تھا۔ دینی تفہیم و تعبیر کے معا ملے میں وہ با لعموم اسلاف کی رائے کے قریب رہنے کو تر جیح دیتے تھے۔ یہ محتاط روش یقیناًخیر کا باعث ہو تی ہے۔ اس میں آپ کسی غلط رائے کا بار اپنے سر لینے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تاہم ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی مو قف کو غلط سمجھتے ہو ئے اُسے محض اس وجہ سے قبول کرلیں کہ وہ اسلاف کی رائے ہے۔ مثا ل کے طورپر وہ اکثر فقہا کی طرح عورت کی گواہی کو آدھی مانتے تھے، لیکن حدود کے مقدمات میں عورت کی گواہی کو قبول کر نے کے حق میں تھے۔ اس باب میں جمہور علما کی رائے یہ ہے کہ وہ حدود میں عورت کی گوا ہی مطلقاً قبول نہیں کر تے۔
غازی صاحب ایک کثیر المطا لعہ اورہمہ جہتی علم کے حامل تھے۔ دین کے حوالے سے وہ متعدد علوم میں ایک استاد کی دسترس رکھتے تھے۔ میں نے انہیں بارہا سنا اور پڑھا۔ سیرتِ صحابہ پر وہ گفتگو کرتے تومعلوم ہو تا کہ انہوں نے حرفِ آخر کہہ دیا ہے۔ اقبال کی عالمانہ تخلیق ’’جاوید نامہ‘‘ کی انہوں نے تسہیل کی۔ یہ کتاب اقبال کے علم اور شاعری کا ایک معجزہ ہے۔ اس میں اقبال نے اپنے پیر رومی کی معیت میں ایک روحانی سفر کیا ہے جس میں وہ متعدد افلاک پر جا تے ہیں اوران شخصیات سے ہم کلام ہو تے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکیں۔ یہ مختلف ادیان اور افکار کے نمائندہ لوگ ہیں۔ اب اقبال ان سے جو مکالمہ کرتے ہیں اور ان کی زبان سے جو کہلواتے ہیں، اس کی تفہیم ممکن نہیں اگر پڑھنے والا ان کے فکر اورفلسفے سے واقف نہیں۔ مثال کے طور پر وہ روس کے بڑے ادیب ٹالسٹائی کا انتخاب کرتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ اس انتخاب کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ ابو جہل سے ایک نو حہ کہلواتے ہیں اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ کیا واقعہ پیش آیا جس نے ابو جہل کی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ غازی صاحب نے ’’جا وید نامہ‘‘ کے مضامین کو ایک عام آدمی کے لیے سہل بنا دیا۔ اس کے مطا لعہ سے ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی فکرِ اقبال کی رنگا رنگی سے واقف ہو جا تا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بین الاقوامی قانون پر لکھا اور بہت عالما نہ انداز میں اس مو ضوع کو دیکھا۔ جنوبی ایشیا کی مسلم فکر پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا۔ ان کی آخری تصنیف عربی زبان میں شیخ احمد سرہندی پر تھی جو بیروت سے شائع ہو ئی۔ غالباً بر صغیر کی ایک بڑی شخصیت کا عربی زبان میں یہ پہلا مفصل تعارف ہے۔
فقہ سے انہیں فطری منا سبت تھی۔ یہ وہ مو ضوع ہے جس پر وہی کچھ کہنے کا مجاز ہے جو ایک طرف روایت سے اچھی طرح آگاہ ہو اور دوسری طرف اپنے عہد کے مسا ئل سے بھی واقف ہو۔ یہ ان کا منفرد اعزازہے کہ دین کے حوالے سے پا کستان میں جو اہم دستاویزات سامنے آئیں، ان میں کسی نہ کسی طرح غازی صاحب کا حصہ رہا۔ مثال کے طور پر قادیانیوں کے حوالے سے جو آئینی ترمیم کی گئی، اس کی تیاری میں وہ مو لا نا ظفر احمد انصاری کے معاون تھے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو حدود قوانین ملک میں رائج ہو ئے، وہ بڑی حد تک ان ہی کے تحریر کردہ تھے۔ وفات سے پہلے وہ وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے۔ اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ میں تھے۔ یہ ملکی قانون اور فقہ میں ان کی دسترس کا اظہار ہے۔ تدریس کے باب میں بھی ان کی خدمات بے پناہ ہیں۔ انہوں نے بہت سے شاگرد چھو ڑے ہیں جن کی حیثیت صدقہ جاریہ کی ہے۔ ان کی تعداد بہت ہے اور وہ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس سال کے آ غاز تک وہ قطر کی ایک یو نیورسٹی میں پڑھا تے رہے ہیں۔
اپنی طا لب علما نہ سر گر میوں میں، میں نے با رہا ان سے رجوع کیا اور ان کے علم سے فائدہ اٹھایا۔میری کتاب ’’علم کی اسلامی تشکیل‘‘ کا مسودہ انہوں نے دیکھا اور اس کو بہتر بنا نے کے لیے مشورے دیے۔یہ ان کی شفقت کا ایک انداز تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ محض میری ذات تک محدود نہیں۔ نہیں معلوم کتنے لوگوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھا یا اور آج ان کے ہاتھ اپنے پر وردگار کے حضور میں ان کی مغفرت کے لیے اٹھے ہیں۔
سچ یہ ہے کہ وہ ایک کامیاب آدمی کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو ئے جسے قرآن مجید نفس مطمئنہ کہتا ہے۔ رات گیارہ بجے کے قریب انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال لے جا یا گیا ۔ چند گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا۔اپنے بھائی محمد غزالی صاحب سے کہا کہ وہ گھر جا ئیں، میں بھی صبح تک لوٹ آؤں گا۔ فجر کی نماز کے لیے وضو کیا،بستر ہی پر نماز پڑھی اور تھوڑی دیر بعد اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہم تفہیمِ مدعا کے لیے اسے موت کہتے ہیں، لیکن یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں قدم ر کھنا ہے۔ وہ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ اب یہاں نہیں ہیں، لیکن اپنی کتابوں ، شاگردوں اور یادوں کے ساتھ یہیں ہیں، یہیں کہیں ہیں۔
لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے
اگر ہو زندہ تو دل نا صبور رہتا ہے
مہ و ستارہ مثالِ شرارہ یک دو نفس
مئے خودی کاابد تک سرور رہتا ہے
فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا
ترے وجود کے مر کز سے دور رہتا ہے!
(بشکریہ روزنامہ اوصاف، اسلام آباد)
اک دیا اور بجھا!
مولانا محمد ازہر
قحط الرجال کے موجودہ افسوس ناک دور میں جب کوئی ایسی ہستی جدا ہوتی ہے جس کا وجود مسائل و افکار سے پریشان اور رہنمائی کی متلاشی امت کے لیے مینارۂ نور کی حیثیت رکھتا ہے تو صدمہ اور غم دو چند ہو جاتا ہے۔اس لیے کہ اب دور دور تک ایسی شخصیات نظر نہیں آتیں جن کا اوڑھنا بچھونا علم ہو اور جن کا تعارف قرآن ،حدیث،فقہ اور علوم و فنونِ شرعیہ پر گہری دسترس ہو۔ معروف محقق و دانش ور،مصنف و ادیب،صاحب علم وفضل ڈاکٹر محمود احمد غازی کا شمار بھی ان اہل علم میں ہوتا تھا جن کی اہلیت و قابلیت اور دینی ثقاہت پر قدیم و جدید علما کا اتفاق تھااور عصری درس گاہوں سے وابستگی کے باوجود دینی مدارس کے اساتذہ و علما بھی ان کی تالیفات و تصنیفات سے استفادہ کرتے نظر آتے تھے۔افسوس کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی۱۶ شوال المکرم ۱۴۳۱ھ (۲۶ ستمبر۲۰۱۰ء) کو علمی و تدریسی حلقوں کو سوگوار چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے،انا للہ و انا الیہ راجعون!
ڈاکٹر صاحب کا تعلق ٹھیٹھ مذہبی گھرانے سے تھا۔داعی کبیر حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے سگے پھوپھا تھے۔آپ کے والد ماجد محمد احمدؒ مرحوم متدین و متبع سنت بزرگ تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی دینی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے درسِ نظامی کی ابتدائی تعلیم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے حاصل کی،جب کہ دینی علوم کی تکمیل شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خانؒ کے مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں کی اور مولانا ہی سے تفسیر قرآن کریم پڑھی۔ قرآن کریم کے پختہ حافظ تھے اور ہر سال رمضان المبارک میں قرآن کریم سنانے کا معمول تھا۔
ڈاکٹر محمود غازیؒ نے سترہ سال کی عمر میں تدریس کا آغاز کیا اور تا دم آخر اس فریضے کو نبھاتے رہے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا اور پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریوں کی تحصیل کے بعد تصنیف و تالیف اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔قدیم و جدید علوم پر دسترس اور خداداد غیر معمولی صفات و کمالات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب مرحوم اپنی زندگی میں بہت سی اہم ذمہ داریوں پر فائز رہے۔ استاذ سے لے کر وزارت تک بہت سے مناصب پر آپ کی صلاحیتیں نمایاں ہوئیں۔حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو تحریر و تقریر کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ عربی ،فارسی،انگریزی،فرانسیسی اور اردو زبان کے بہترین خطیب و ادیب تھے۔ ہفت زبان ہونے کا محاورہ ڈاکٹر صاحب کے لیے مجازاً نہیں، حقیقتاً استعمال ہوتا تھا۔سرکاری مناصب پر فائز رہنے کے باوجودڈاکٹر صاحب قومی،ملی اور دینی تحریکوں کے پشت پناہ رہے۔قادیانی تحریک کے خلاف مسلمانوں کے متفقہ موقف کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے گراں قدر خدمات انجام دیں اور جنوبی افریقہ کی ایک عدالت میں قادیانیوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کا متفقہ موقف پیش کرنے کی ڈاکٹر صاحب کو سعادت عطا کی گئی۔
جامعہ خیر المدارس ملتان نے جب عصری تقاضوں کے پیش نظر ’’خیر المعارف‘‘کے نام سے ایک جدید درس گاہ قائم کی تو اس کے رسمی افتتاح کے لیے جامعہ کے مہتمم مولانا قاری محمد حنیف جالندھری نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں(۲۰۰۰ء)مذہبی امور کے وزیر تھے۔افتتاح کے موقع پر انہوں نے دینی علوم کی عظمت و اہمیت پر فاضلانہ خطاب فرمایا۔ اس کے ساتھ ایسے اہل علم کی ضرورت پر زور دیا جو دور جدید کے رجحانات پر ناقدانہ نظر رکھتے ہوں۔ ’’کتاب الآرا‘‘ میں اپنے تأثرات رقم کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے لکھا:
’’ادارہ خیر المعارف پاکستان میں دینی تعلیم کے میدان میں ایک منفرد اور انقلابی تجربہ ہے۔اس ادارے کا مقصد ایسے علمائے دین تیار کرنا ہے جو ایک طرف سلف صالحین کے تقویٰ و للہیت کی صفت کے مظہر ہوں اور دوسری طرف جدید دور کے تقاضوں اور فکری رجحانات سے براہِ راست اور ناقدانہ واقفیت رکھتے ہوں۔مجھے امید ہے کہ ادارہ خیر المعارف اپنے پاک نفس اور پاک باز مدرسین کی اعلیٰ دینی روایات کو بلند سے بلند تر کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور میں دینی قیادت فراہم کر سکنے اور دورِجدید کے رجحانات پر ناقدانہ نظررکھنے والے اہل علم پیدا کرے گا۔‘‘
حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا شمار امت کے ان چیدہ چیدہ افراد میں ہوتا ہے جو ان کے بقول دور جدید کے رجحانات پر ناقدانہ نظر رکھتے تھے اور امت کو دینی قیادت فراہم کر سکتے تھے۔ راقم السطور کو دو چار مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں بیٹھنے اور کسی حد تک استفادہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ غیر معمولی علمی مقام کے باوجود ان کے عجز وانکسار،سادگی،نرم مزاجی اور دھیمے پن نے احقر کو بہت متأثر کیا۔ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سلاست، بلاغت، متانت اور فقاہت کا مرقع ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی میں ایک مجلس میں موضوع گفتگو مسلمانوں کی علمی،عملی اور معاشی زبوں حالی اور صورت حال کی تبدیلی،امکانات اور تجاویز تھا۔ اس مجلس میں بھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو نہایت پر مغز،معلومات افزا اور فاضلانہ تھی۔مسلمانوں میں پائی جانے والی ایک غلط فہمی کی اصلاح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بہت سے حضرات سادہ لوحی سے مغرب کا مطالعہ کرتے ہیں اور مغرب کے ظاہری دعووں سے متأثر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے مذہب کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب مغرب مذہبی تعصب سے آزاد ہو گیا ہے جب کہ حقیقت اس کے بالکل بر عکس ہے اور مغرب کی ہر چیز عیسائی تہذیب و تمدن ،عیسائی روایات اور عیسائی تعصبات پر مبنی ہے۔یہ بات خود مغربی مصنفین نے بھی کہی ہے،لہٰذاعیسائیت کو مغرب سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔یہ سمجھنا کہ مغربی دنیا سیکولر ہے، اس لیے اسے مذہبی مفادات سے دلچسپی نہیں اور وہ مذہبی عصبیت سے بالاتر ہے، سادہ لوحی بلکہ بے وقوفی ہے۔
اپنی بات مدلل کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا جس سے مسلمانوں کے بارے میں اہل مغرب کی عصبیت کا اندازہ ہوتا ہے۔انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس ہوئی جس میں دنیا بھر کے دانش وروں کو مدعو کیا گیا تھا۔اس میں عیسائی مندوبین کی تعداد ۶۰۰ تھی جب کہ پورے عالم اسلام کی نمائندگی کرنے والے مسلمان صرف تین تھے۔ سامعین جرمنی کے صف اول کے لوگ تھے۔ اس کانفرنس میں مجھے جس موضوع پر خطاب کا موقع ملا،وہ تھا:’’یورپ کی ٹیکنالوجی سے مسلمانوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے‘؟‘ اس پر میں نے عرض کیا کہ جب انگریز برصغیر میں آئے تو ان کی تہذیب و معاشرت،کلچر ،روایات اور ٹیکنالوجی کے بارے میں تین قسم کے نظریات اور رویے سامنے آئے۔بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے مغرب کی ہر چیز کو ایک خطرہ سمجھا اور تہذیب و معاشرت سے لے کر ٹیکنالوجی تک مغرب سے درآمد شدہ ہر چیز کا مکمل مقاطعہ یا بائیکاٹ کر دیا۔ ایسے افرادکی تعداد بہت کم تھی اور یہ نظریہ بعدازاں ختم ہو گیا۔اب اس نظریہ کے لوگ نہیں پائے جاتے۔دوسرا نقطۂ نظر ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بلا استثنا انگریزوں کی ہر چیز کو قبول کر نے کا نظریہ پیش کیا۔یہ نظریہ ابھی تک چل رہا ہے لیکن سو سال میں اس کا نتیجہ مسلمانوں کی ملی و تہذیبی تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلا ۔ تیسرا رویہ اور نقطہ نظر یہ تھا کہ مغرب سے خیر کی چیزیں لے لی جائیں اور شر کی چیزیں چھوڑ دی جائیں جسے عربی میں ’’خذ ما صفا ودع ما کدر‘‘ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معقول و معتدل نظریہ ہے اور مسلمانوں کو اسے اختیار کرنا چاہیے مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے خطاب کے بعد جرمنی کے ایک سامع نے کہا کہ یہ آپ کا خیال خام ہے کہ آپ مغرب کی اچھی چیزوں سے استفادہ کریں اور جو آپ کی نظر میں اچھی نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیں۔مغرب سے استفادہ کے لیے آپ کو مغرب کی تمام شرائط ماننا ہوں گی۔مثال کے طور پر اگر آپ مغرب کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو سیکولر ڈیموکریسی اور مساواتِ مرد و زن کا فلسفہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ اس شخص کے ذاتی خیالات ہوں اور یہ شخص مسلمانوں کے بارے میں متشددانہ نظریہ رکھتا ہو،لیکن جب مجھے دوسرے مقامات پر جانے،لوگوں سے ملنے ،ان کے نظریات معلوم کرنے اور ان کی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں پورا مغرب یک زبان ہے اور وہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے ،دین اور خیر کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔
اس گفتگو سے شرکاے محفل کو اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب مغربی افکار و نظریات پرنقد و محاکمے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔اس موضوع پر آپ کی کتاب’’اسلام اور مغرب کے تعلقات‘‘ اردو خواں حضرات کے لیے لائق مطالعہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحبؒ آج ہم میں نہیں رہے،اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ تو کجا شاید دینی مدارس کے طلبہ کو بھی اس نقصان اور خلا کا اندازہ نہ ہو سکے جو ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی وفات سے ہوا ہے۔
جواب اس بات کا یارانِ محفل سوچنا ہوگا
ہمارے بعد ہم جیسے کہاں سے لوگ لاؤ گے
حق تعالیٰ شانہ ڈاکٹر صاحب مرحوم و مغفور کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائیں، آمین
ایک معتدل شخصیت
مولانا محمد اسلم شیخوپوری
بیس بائیس سال پہلے یہ ناچیز ماہنامہ ’’الاشرف‘‘ کا مدیر تھا۔ یہ ادارت اسے اتفاق سے مل گئی تھی، ورنہ وہ اس کا ہرگز اہل نہ تھا۔ الاشرف کے انتظامی معاملات کی دیکھ بھال مولانا محمد شاہد تھانوی رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اچانک عارضہ دل میں مبتلا ہوگئے اور پھر اسی مرض میں ان کا انتقال ہوگیا۔ تعزیت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا تو وہاں مہمانوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ ان مہمانوں میں سے ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب ہیں۔ کاندھلہ کے مشہور علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ انٹرنیشنل لیکچرار اور مبلغ ہیں۔ سات بین الاقوامی زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہے۔ درسِ نظامی کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کررکھی ہے۔ مدارس کی مخصوص فضا میں نشوونما پانے والے اس ’’ملا‘‘ نے جب اس خطیب اور مبلغ کے سراپا پر نظر ڈالی تو اسے کوئی ایسی نمایاں چیز دکھائی نہ دی جس کی وجہ سے وہ علامہ فہامہ جیسے القاب کے حقدار ٹھہرتے ہوں۔ دل ہی دل میں وسوسہ آیا: ’’خاندانی نسبت بھی کیا چیز ہے جو صاحبزادوں کے سرپر عزت اور شہرت کا تاج رکھ دیتی ہے، اگرچہ وہ مطلوبہ صلاحیت سے محروم ہی کیوں نہ ہوں۔‘‘
پروفیسروں، مسٹروں اور ڈاکٹروں کے بارے میں دل میں یہ خیال جاگزیں تھا کہ یہ علمی تصلب اور علمی پختگی سے خالی ہوتے ہیں اور عوام پر اپنا رعب ودبدبہ محض ڈگریوں اور جدید اسلوبِ گفتگو میں مہارت کی وجہ سے قائم رکھتے ہیں۔ جن شخصیت کا تعزیتی اجتماع میں تعارف کرایا گیا تھا، انہیں بجائے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور ماہر علوم عقلیہ ونقلیہ کے ڈاکٹر محمود احمد غازی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا یہ بھی ویسے ہی ڈاکٹر اور پروفیسر ہوں گے جیسے اس قبیلے کے دوسرے افراد ہوتے ہیں۔ بات بات پر مغرب کی ترقی کے حوالے دینے والے، قدیم علما کو حقارت کی نظر سے دیکھنے اور اپنی علمیت کے بارے میں دھوکا کھا جانے والے، لیکن جب انہیں براہِ راست سننے اور ان کی کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو اپنی عاجلانہ سوچ اور وساوس پر سخت افسوس ہوا۔
حقیقت یہ ہے کہ وسعت مطالعہ، ذکاوت اور حافظہ قدیم وجدید کے اجتماع، اظہار مافی الضمیر کی قدرت، اسلام دشمن تحریکوں اور فتنوں سے آگاہی، تدریس، تقریر اور تحریر میں یکساں مہارت جیسی صفات جو باری تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب میں جمع کردی تھیں، ان صفات کے حامل موجودہ دور میں دوچار ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے تو پچیس کے قریب تصنیفات میں سے ان کی ہر تصنیف ہی ان کی متانت وثقاہت اور علمیت اور وسعتِ نظر کا شاہکار ہے، مگر چھ جلدوں میں ان کے جو محاضرات شائع ہوئے ہیں، کم ازکم اس عاجز کے علم میں ایسی ایسی کتابوں کے حوالے ہیں جن کا مطالعہ ہمارے ہاں متروک ہوچکا ہے اور ایسی ایسی معلومات ہیں کہ ذوقِ مطالعہ رکھنے والا انسان وجد میں آجاتا ہے۔ اس قسم کے متعدد محاضرات اور خطبات عربی اور اُردو میں شائع ہوچکے ہیں، مگر ان میں سے اکثر حقیقت میں وہ مقالات ہیں جنہیں پہلے حرف بہ حرف لکھا گیا اور پھر کسی علمی اجتماع میں یہ مقالات پڑھ کر سنادیے گئے مگر جناب غازی صاحب کے جو محاضرات طبع ہوئے ہیں، وہ ان کے ایسے لیکچر ہیں جو انہوں نے خواتین وحضرات کے منتخب اجتماع میں مختصر یادداشتوں کی بنا پر زبانی ارشاد فرمائے اور پھر صوتی تسجیل سے انہیں صفحہ قرطاس پر منتقل کیا گیا۔ یہ محاضرات چھ ضخیم جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ہر جلد ۱۲ خطبات پر مشتمل ہے۔ ان چھ جلدوں میں قرآن، حدیث، سیرت، فقہ، تصوف اور معیشت وتجارت کے مختلف پہلو زیربحث لائے گئے ہیں۔
ان محاضرات سے جہاں غازی رحمہ اللہ کے بے مثال حافظہ، وسعتِ فکرونظر اور علمی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے وہیں ان کی صفتِ اعتدال بھی نکھر کر سامنے آتی ہے اور اعتدال ایسی صفت ہے جو اہمیت کے باجود مفقود ہوتی جارہی ہے۔ ہمارے ہاں ہر معاملے میں افراط وتفریط پائی جاتی ہے۔ تبلیغ ودعوت ہو یا جہاد وقتال، سیاست وقیادت ہو یا طریقت وشریعت، مدح اور منقبت ہو یا تردید اور تنفید، ذکروعبادت میں انہماک ہو یا کسبِ معاش میں مشغولیت، ابلاغ کے جدید وسائل سے استفادے کا معاملہ ہو یا اختلافی مسائل میں بحث ومناظرہ کا، ہر جگہ اور ہر شعبہ میں افراط وتفریط آگئی ہے۔ کوئی اتنا تنگ نظر ہے کہ اس کے نزدیک دین نام ہے چند فرقہ ورانہ مسائل میں تشدد کرنے اور ظاہری شکل وصورت کو ’’باشرع‘‘ بنانے کا۔ کوئی ایسا وسیع الظرف ہے کہ وہ کفروایمان کا فرق بیان کرنے کو بھی فرقہ واریت سمجھتا ہے اور ظاہری اعمال کی اس کے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں۔ تعریف اور تنقید کو دیکھیں تو بعض حضرات جب تک اپنے مخالفوں کو ابن اُبی اور ابولہب سے بدتر اور اپنے گروہ کے مشائخ کو ابن تیمیہ اور ابن قیم سے برتر ثابت نہ کردیں، انہیں چین ہی نہیں آتا، جبکہ ڈاکٹر صاحب فکرونظر اور کردار وعمل کے اعتبار سے انتہائی معتدل شخصیت تھے۔ اپنے دعوے کی تائید میں صرف دو مثالیں ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔
جب ڈاکٹر صاحب نے سیرت پر محاضرات پیش کرتے ہوئے ’’مطالعہ سیرت۔ پاک وہند‘‘ کے عنوان سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے یوپی کے لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور کی کتاب ’’Life of Muhammad‘‘ اور اس کے جواب میں سرسید احمد خاں نے جو کتاب لکھی تھی، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس جواب کے لکھنے میں سرسید احمد خاں نے جو قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کا بھی انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا کہ یہ سب کچھ بلاکم وکاست بیان کردیا جاتا، لیکن یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا: ’’بطورِ سیرت کے ایک ادنیٰ طالب علم کے مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ سرسید کے بہت سے بیانات سے اتفاق کرنا مشکل ہے۔ کئی جگہ انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہیں۔‘‘ اس خطاب کے اختتام پر ان سے سوال کیا گیا: ’’کیا سرسید احمد خاں منکر حدیث تھے؟‘‘ انہوں نے جواب دیا: ’’یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ منکر حدیث تھے یا نہیں، لیکن ان کے بہت سے مذہبی خیالات سے اہلِ علم کو اتفاق نہیں تھا۔ یہ خیالات کمزور دلائل اور مغرب سے مرعوبیت کے نتیجے میں اختیار کیے گئے تھے۔ خود مجھے بھی ان خیالات سے اتفاق نہیں۔‘‘
اسی طرح ایک موقع پرا ن سے سوال کیا گیا تھا: ’’جن معاملات میں فقہا کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں کس کی بات کو صحیح مانیں اور کس بنیاد پر؟‘‘ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا: ’’بنیادی بات تو یہ ہے جس بات کو آپ دلیل کی بنیاد پر زیادہ صحیح سمجھیں، اس کی پیروی کریں۔ جو چیز قرآن وسنت کے زیادہ قریب ہو، اس پر عمل کریں اور جو چیز قرآن وسنت کے حکم سے ہم آہنگ نہ ہو، اس پر عمل نہ کریں، لیکن اس کام کے لیے بڑے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ یا تو وہ گہرا اور عمیق علم ہمارے پاس ہو اور اگر ہمارے پاس اس درجے کا علم نہ ہو تو جس کے علم پر ہمیں اعتماد ہو، اس سے پوچھ کر عمل کریں۔‘‘
(ہفت روزہ ضرب مومن کراچی)
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ، ایک مشفق استاد
شاہ معین الدین ہاشمی
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر انتظام ۱۹۹۳ء میں ایم فل علوم اسلامیہ کی ورکشاپ کے دوران ہوئی۔ وہ ریسورس پرسن کی حیثیت سے ورکشاپ میں تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس ورکشاپ میں علوم اسلامیہ کے بنیادی مصادر پر تعارفی گفتگو فرمائی۔ یہ گفتگو اتنی علمی اور موضوع پر اتنی مربوط تھی کہ اس سے قبل نہ تو کہیں پڑھی اور نہ سنی تھی۔ اس گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے علوم اسلامیہ کے مصادر سے متعلق تفصیل سے بات کی۔ علوم القرآن، علوم الحدیث، فقہ، تصوف کے تمام بنیادی مصادر پر تعارفی گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب کے اس لیکچر نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس سے ایک طرف مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمیں اپنی تراث کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، دوسری طرف غازی صاحب سے قلبی تعلق بڑھتا چلا گیا۔
اس کے بعد دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب ہم ایم فل علوم اسلامیہ کے تھیسس کے لیے عنوان کی تلاش کے مرحلے میں تھے۔ یہ ۱۹۹۴ء کی بات ہے کہ شعبہ علوم اسلامیہ نے میری ریسرچ کے لیے عنوان منظور کرلیا اورمجھے ’’عہد نبوی میں اسلامی ریاست کے داخلی نظم و نسق‘‘ پر خطہ بنانے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع کو عرب قبائل کی شیرازہ بندی کے ساتھ مخصوص کر دیا اور میری خوش قسمتی کہ میرا اشراف بھی قبول فرما لیا۔ اپنے موضوع پر کام کرنے کے لیے ہدایات لینے کی غرض سے میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ دعوۃ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ اگرچہ ملاقات طے شدہ نہ تھی اور آپ کی دیگر مصروفیات بہت تھیں، تاہم آپ نے مجھے اندر بلا لیا ۔ ساتھ ساتھ دفتری لوگوں سے ملتے رہے اور مجھے موضوع سے متعلق بنیادی باتیں بتاتے رہے۔ یہ ملاقات تقریباً پچاس منٹ تک رہی جس میں مجھے بیس پچیس منٹ ملے۔ آپ نے موضوع پر مجھے ابتدائی اور اہم نکات بتائے۔ اس پہلی ملاقات میں ڈاکٹرصاحب نے میرے ذہن کو سیرت کے ان اطراف کی طرف منتقل کر دیا جن پر پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا یقین یہ ہے کہ مجھے سیرت پر پڑھنے پڑھانے یا کچھ لکھنے لکھانے کاجو موقع ملا ہے، وہ اسی پہلی ملاقات کا ثمر ہے اور یہ ملاقات شاید ساری زندگی مجھے سیرت پر کام کرنے میں مدد دیتی رہے گی۔
ڈاکٹرغازیؒ گزشتہ دو دہائیوں سے اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہے جس کی وجہ سے آپ کی مصروفیات زیادہ ہو گئیں۔ اس کے باوجود آپ نے اپنا استاد ہونے کے تشخص کو نمایاں رکھا اور طلبہ سے تعلق میں کمی نہ آنے دی۔ میرے سمیت آپ کے اکثرشاگرد ہمیشہ وقت لیے بغیر ہی ملاقات کی غرض سے جاتے رہے۔ آپ طلبہ کے معاملے میں نہایت تحمل سے کام لیتے تھے اور نہایت شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے طلبہ کو زیادہ دیر تک انتظار میں نہیں بٹھاتے تھے اور نہ ہی مصروفیت کی وجہ سے واپس بھیجتے تھے۔
ڈاکٹر صاحب مرحوم خود بھی کثیر المطالعہ تھے۔ اسی طرح وہ اپنے طلبہ میں بھی مطالعہ کا شوق پیدا کرتے رہتے تھے اور ان کی مناسبت سے مختلف کتب کی طرف نشان دہی بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ڈاکٹر فواد سیزگین کی کتاب Geschischte der Arabischen Schriftum (تاریخ التراث العربی)اس قابل ہے کہ اس کے براہ راست مطالعہ کے لیے جرمن زبان سیکھ لی جائے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے چار چھ مہینے لگا کر جرمن زبان کو اتنا سیکھ لیا ہے کہ اب میں آسانی سے اس زبان میں لکھے گئے مصادر سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے کہا کہ آپ نے قبائل عرب کے حوالے سے کام کیا ہے، لہٰذا آپ ابوالفرج اصبہانی کی کتاب الاغانی کا، جو کہ بائیس یا چوبیس جلدوں پر مشتمل ہے، شروع سے آخر تک مطالعہ کریں کیونکہ اس میں سیرت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق خاصا مواد موجود ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے یہ کتاب شروع سے آخر تک مکمل پڑھ لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے امام شافعی کی کتا ب ’’الام‘‘ کا سات مرتبہ شروع سے آخر تک بالاستیعاب مطالعہ کیا۔ درجنوں مصادر علوم اسلامیہ ایسے تھے جنہیں آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا۔
ایم فل علوم اسلامیہ کی تکمیل کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے جلدپی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن کروا نی چاہیے۔ میں نے جلدی میں معاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خاکہ تیار کیا اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنے ارادہ اور خواہش کا اظہار کیا اور اپنا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس پر رائے دیں۔ خاکہ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال ؒ کا یہ شعر سنایا:
نالہ ہے بلبل شوریدہ ترا خام ابھی
اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی
اور اس موضوع پر مختلف کتب کی طرف نشان دہی فرمائی اور مزید مطالعہ کاکہا ۔ پھر چار برس تک مختلف اوقات میں مختلف کتب کے مطالعہ کا حکم دیتے رہے۔ بالآخر ۲۰۰۰ء میں جب میں نے اپنا خاکہ دوبارہ پیش کیا تو آپ نے نہ صرف اس سے اتفاق فرمایا بلکہ اس کا اشراف بھی قبول فرمایا۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں گزشتہ پندرہ برسوں کے تجربہ میں،میں نے یہ دیکھا کہ طلبہ کی رہنمائی کے حوالے سے آپ کو جب بھی کلیہ میں آنے کی دعوت دی گئی، آپ نے ایک مرتبہ بھی دعوت رد نہیں کی بلکہ نہایت خوشی خوشی کلیہ میں تشریف لاتے تھے اور اپنی دیگر مصروفیات کو ترک یا مؤخر کردیتے۔ اس کے لیے آپ عام طور پر مغرب کے بعد کا وقت پسند فرماتے تھے تاکہ وقت تنگ نہ ہو اورطلبہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔
ڈاکٹر صاحب کے فکر کی بہت سی اہم جہات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا، لیکن اس بات پرآپ کا ارتکاز رہا اور آپ اپنے طلبہ کے سامنے مختلف اوقات میں اس بات کو پرزور طریقے سے بیان کرتے رہے کہ اسلامی تحقیق کا سب سے بڑا کام تعمیر فکر کا ہے۔اس سے ان کی مراد اسلامی نقطہ نظر سے تمام علوم و فنون کی ترتیب نو اور تشکیل جدید ہے۔ اس میں جدید علوم کی تشکیل بھی شامل ہے اور قدیم اسلامی علوم کی تعمیر نو بھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خیال میں تطہیر فکر کا عمل اس سے قبل ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ رائج الوقت علوم و فنون کا اسلامی نقطہ نظر سے تنقیدی جائزہ لے کر کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے۔ لیکن ان کے نزدیک علوم وفنون کی تدوین نوکے اس عمل کے انتظار میں ہم دوسرے شعبوں میں اسلامی نقطہ نظر سے اصلاحات کے عمل کو نہ تو ملتوی کر سکتے ہیں اور نہ مؤخر کر سکتے ہیں۔ ان کی رائے میں یہ دونوں کام ایک ساتھ ہی ہونے چاہئیں بلکہ اگر یہ دونوں کام ایک ساتھ شروع کیے جائیں تو دونوں ایک دوسرے کے ممد ومعاون اور تکمیل کنندہ ثابت ہوں گے اور ایک کی راہ میں حائل دشواریوں کو دور کرنے کی ہر کوشش دوسرے کی راہ میں حائل دشواریوں کو ختم کرنے میں بھی مدد دے گی۔ ڈاکٹر صاحب تعمیر و تطہیر فکر کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے اور اپنے طلبہ اور دیگر اہل علم کو اس جانب توجہ دلاتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے خیال میں علوم کی تنقید و تنقیح کے لیے امت مسلمہ کے پاس اب زیادہ وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مستقبل قریب میں امت مسلمہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوگئی تو خیر، ورنہ اسلامی اقدار و تہذیب کا احیا شاید ممکن نہ ہوسکے گا۔
علامہ اقبالؒ نے آج سے ساٹھ برس قبل جو بات اسلامی فقہ کے بارے میں کہی تھی، ڈاکٹر صاحب مرحوم کے خیال میں وہ آج سارے علوم و فنون پر صادق آرہی ہے اوراس وقت اس کی جتنی اہمیت تھی، آج اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا:
’’میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص زمانہ حال کے جورس پروڈنس (اصول قانون) پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ابدیت کوثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجدد ہوگا اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہوگا۔ قریباً تمام ممالک اسلامیہ میں مسلمان یا تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یا قوانین اسلامیہ پر غور کررہے ہیں۔ غرض یہ وقت عملی کام کا ہے کیونکہ میری رائے میں مذہب اسلام گویا زمانہ کی کسوٹی پر کسا جارہا ہے اور شاید تاریخ اسلام میں ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔‘‘
ڈاکٹر غازیؒ نے اپنی ساری زندگی ایسے ادارے اور رجال کار کی تیاری کے لیے وقف کر دی جو علامہ اقبال کے اس تصور کی تکمیل کر سکیں۔
ڈاکٹر صاحب کی فکر کا ایک اہم پہلو برصغیرپاک وہند کے دینی مدارس،ان کا نصاب اور ان کے فاضلین سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب مدارس علوم دینیہ کے بارے میں نہایت متفکر رہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس نظام میں پڑھنے والے طلبہ بالخصوص ملک پاکستان میں اور بالعموم پوری دنیا میں خاص کردار ادا کرسکتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے لیے کسی بڑے پیمانے کی نہیں بلکہ تھوڑی لیکن مناسب تبدیلیوں کی ضرورت ہے جن میں ایک ضروری چیز زبان ہے۔ مدارس کے طلبہ کو عربی اور انگریزی زبانوں کو بالخصوص اور دیگر اہم زبانوں کو بالعموم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ زبانوں کو سیکھنے سے معاشر ے میں علما کی افادیت کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ درس نظامی کے نصاب کے مقصد سے متعلق ایک مرتبہ فرمایا: سوال یہ ہے کہ درس نظامی کا یہ نصاب ملا نظام الدین سہالوی ؒ مرحوم و مغفور نے کیوں اور کس مقصد کے تحت مرتب کیا تھا؟ اس پر اگر ذہن صاف ہو اور تاریخی حقائق سامنے ہوں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بر صغیر میں سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں (جس کو آپ بر صغیر کی اسلامی تاریخ کا دور زوال اور دور انحطاط بھی کہہ سکتے ہیں) ریاستی نظام چلانے ،اسلامی عدالتوں کو قاضی ،مفتی اور مقنن فراہم کرنے کی خاطر یہ نصاب تیار کیا گیا تھا۔ یہ زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ابتدائی دور تھا۔جب اٹھارویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے شاہ عالم سے دیوانی خرید لی تو کمپنی کے زیر انتظام صوبوں کے بارے میں یہ شرط رکھی گئی کہ وہاں کا نظام بدستور فقہ حنفی کے مطابق چلتا رہے گا۔اس نظام کے لیے کمپنی کے کار پردازوں نے بھی اپنے اہتمام میں درس نظامی کے کئی ادارے قائم کیے۔ یہ سلسلہ ۱۸۵۷ء میں سلطنت مغلیہ کے مکمل اور حتمی سقوط تک جاری رہا۔ بہر حال اس کے بعدچونکہ یہی نصاب موجود تھا اور اسی نصاب کے تیار کردہ علما دستیاب تھے،اس لیے جب دار العلوم دیو بند اور دوسرے مدارس قائم ہوئے تو انہوں نے اسی نصاب کو قابل عمل پایا اور اس کو اختیار کر لیا۔ لیکن دار العلوم دیوبند کے قیام کے بعد خود اس نصاب کو ’’حقیقی درس نظامی‘‘ نہیں رہنے دیا۔ آج کا رائج الوقت درس نظامی اصل درس نظامی سے بہت مختلف چیز بن چکا ہے، لیکن تاریخی تسلسل میں اگر اس کو درس نظامی کہا جائے تو اس میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی۔
ایک گفتگو کے دوران دینی مدارس کے مقصد سے متعلق فرمایا کہ ان اداروں کا بنیادی مقصد دینی علوم کے محققین، محدثین، مفسرین، فقہا، مبلغین اور عربی دان پیدا کرنا ہے۔ ان اداروں کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ان میں محدثین، مفسرین، متکلمین اور فقہاے اسلام کے بجائے کمپیوٹر کے ماہرین پیدا ہوں۔ یہ دینی تخصص کے ادارے ہیں اور انہی رجال کار کی تیاری کے ادارے رہیں گے،لیکن ہم سب لوگ فرداً فرداً یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ دینی مدارس کے متخصصین علما، فقہا، محدثین، مفسرین کو عصر حاضر میں اپنے تخصص کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس تخصص کے مطابق، ملکی نظام کو ڈھالنے اور اس کے مطابق ملک کے مختلف اداروں کی تشکیل نو کے لیے بعض ایسی جزوی، معنوی تبدیلیوں یا جامع علوم اور مہارتوں کی ضرورت ہے جس کے بغیر دور جدید میں دینی تعلیم کے تقاضوں پر کما حقہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا ۔
درس نظامی اور موجودہ حکومتی نظام کی دو الگ جدولوں کے نقصان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ’’دو متوازی جدولوں کا وجود ہمارے ملک میں خاص طور پر اور دنیاے اسلام میں عام طور پر دین ودنیا میں تفریق کے نظریہ کو فروغ دے رہا ہے اور یوں سیکولر ازم کے غیر اسلامی تشخص کو پروان چڑھا رہا ہے۔ سیکولر ازم کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم اور مذہبی ہدایت ورہنمائی کو زندگی کے عملی میدان سے نکال دیا جائے جیسا کہ مغرب میں ہوا ہے اور دوسرے کئی ممالک میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے ان دو متوازی نظاموں کی وجہ سے اس کومزید مہمیز مل رہی ہے۔ تعلیم کے ایک نظام کا دائرہ صرف مسجد تک محدود رہے اور دوسرا نظام، زندگی کے بقیہ سب پہلوؤں کو چلاتا رہے تو اسی کو سیکولر ازم کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے عملاً سیکولر ازم ہمارے ملک میں آچکا ہے اور اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ بھی عرض کرنے کے لیے تیار ہوں کہ علما کے اس رویے سے سیکولر ازم کو فروغ ملا ہے۔‘‘
سیکولر ازم کی نظریاتی بنیاد کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ’’وہ بنیاد موجودہ بائبل میں مندرج ہے (کس نے اور کب اس جملے کا اندراج کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے) کہ ’’جو قیصرکا ہے، وہ قیصر کو دے دو اور جو اللہ کا ہے، وہ اللہ کو دے دو۔‘‘ اگر یہ سیکولر ازم کی بنیاد ہے تو پھر یہ بھی سیکولر ازم ہے کہ جو مذہبی تعلیم ہے، وہ مسجد میں ہو اور جو غیر مذہبی تعلیم ہے، وہ مسجد سے باہر ہو۔مسجد سے باہر دی جانے والی تعلیم معاشی، معاشرتی اور سرکاری نظام چلا رہی ہواور مسجد کی تعلیم کا دنیا کے ان مشاغل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہی سیکولر ازم ہے۔‘‘
انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے زیر اہتمام دینی مدارس میں تعلیم کے حوالے سے ایک سیمینار میں جس میں راقم بھی شامل تھا ،ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ’’پچھلے چند مہینوں میں مجھے خاص طور پرملک کے انتہائی جید اہل علم سے اور بالخصوص بعض جید محترم علمائے کرام سے تبادلہ خیال اور استفادے کا موقع ملا ہے۔ علمائے کرام کی قابل لحاظ تعداد اس ضرورت کو محسوس کرتی ہے کہ’’دینی مدارس کے نظام اور نصاب میں مثبت تبدیلی لائی جانی چاہیے‘‘ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ملک کی دینی قیادت میں بعض انتہائی قابل احترام بزرگ ابھی تک ایک مختلف تصور پر سختی کے ساتھ قائم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے بعض کی خدمت میں نیاز حاصل کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے جنہوں نے ہر ایسے موضوع پر کسی قسم کی گفتگو کرنے، گفتگو میں حصہ لینے یا گفتگو میں شریک ہونے سے صاف صاف انکار فرمایا جس کا مقصد یہ ہو کہ دینی مدارس کی پیداوار یا دینی مدارس کے طلبہ کا معاشرے میں مسجد کی خدمت کے علاوہ بھی کوئی اور رول یا کردار ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے واضح اور دوٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ :ہم تو مسجد کے ٹکڑوں پر پلنے والے کٹھ ملا ہی تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں اور دینی مدارس اس وقت تک ہی قائم رہ سکتے ہیں جب تک ان کو صرف مسیتیے پیدا کرنے ہوں۔ یہ الفا ظ خود انہوں نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے۔‘‘
ڈاکٹر صاحب کے خیال میں اسلامی تعلیمات کی کما حقہ تفہیم دینی مدارس کا امتیاز ہے۔ آپ دینی مدارس کے کردار کو وسیع اور مفید بنانا چاہتے تھے۔ پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے زیر اہتمام ایک اجلاس میں آپ نے فرمایا: ’’کم و بیش گزشتہ ۳۵، ۴۰ سال سے میرے ذہن میں یہ خیال نہایت مستحکم ہے کہ ملک میں دینی اور اسلامی تعلیم کا ایک نیا جامع اور متوازن نظام وضع کیا جائے۔ اس نئے نظام کا بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایسے اہل علم اور ایسے علما تیار کیے جائیں جو ایک طرف اسلام کی تعلیمات کو کما حقہ گہرائی اور تعمق کے ساتھ سمجھتے ہوں، اخلاق و کردار میں ائمہ سلف کی تعلیم اور اسوہ حسنہ کا نمونہ ہوں اور دوسری طرف وہ دور جدید اور نئی تعلیم کی تحدیات (Challanges) کو ایک ناقدانہ انداز میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے عہد جدید کے امور و حالات کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے نہایت ضروری ہے۔‘‘
ایک مرتبہ آپ نے فرمایاکہ ہمیں جس دور میں، جن حالات اور جس ماحول میں کام کرنا ہے، جن مسائل کا حل پیش کرنا ہے اور جن رکاوٹوں کو دور کرکے مملکت میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے کوشاں رہنا ہے، ان سب سے گہری اور ناقدانہ واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت عمرؓ کی ایک مثال ذکر کی کہ آپؓ نے ایک مرتبہ کسی کو ایک خاص ذمہ داری پر فائز کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا۔ ایک صاحب کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ وہ بہت متقی، پرہیزگار ہیں اور اتنے نیک ہیں کہ ’’کانہ لا یعرف الشر‘‘ (گویا کہ وہ شر کو جانتے ہی نہیں)۔ حضرت عمرؓ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے ایسا آدمی نہیں چاہیے جو شر کو نہیں جانتا، اس لیے کہ ’’من لم یعرف الشر یوشک ان یقع فیہ‘‘ لہٰذا معلوم ہوا کہ شر سے بچنے کے لیے شر کو جاننا ضروری ہے۔اس بات کی مزید تفہیم کے لیے آپ نے ایک اور مثال بھی ذکر فرمائی۔ وہ یہ کہ اگر امام محمد کی کتابیں نہ ہوتیں تو امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کا نوے فی صد حصہ ہم تک نہ پہنچ سکتا۔امام محمد بن حسن الشیبانی جب اپنی کتابیں مرتب فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ بازار میں گزاریں اور مختلف تجا رتی وبازاری سرگر میوں کا بذات خود جائزہ لیتے رہا کریں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ کاروبار کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح کے مسائل ومشکلات کا کاروباری طبقے کو واسطہ پڑتا ہے تاکہ اسلامی فقہ کی تدوین میں ان مسائل ومشکلات کا خیال رکھا جا سکے۔بعد کے فقہاء کرام نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے۔کہ ’’من لم یعرف اھل زمانہ فھو جاہل‘‘ یا ’’لیس بفقیہ‘‘ یعنی جو اپنے زمانے کے حالات نہیں جانتا، اس کو فقیہ بننے کا حق نہیں۔دوسرے لفظوں میں جو فقیہ بننا چاہتا ہے،جہاں وہ اسلامی علوم میں گہری بصیرت رکھتا ہو، وہاں اس کو زمانے کے حالات میں بھی گہری بصیرت رکھنی چاہیے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ قدیم وجدید اسلامی افکار کے جامع تھے۔ ایک طرف آپ قدیم دینی افکار کے امین تھے اور دوسری طرف تیزی سے تغیر پذیر جدید معاشرے پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مقصد زندگی صرف اور صرف اسلام کا احیا اور اعلاء کلمۃ اللہ تھاجس کے لیے آپ نے اپنی حیات کے لمحات کو صرف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔
مصادر ومراجع
ڈاکٹر محموداحمد غازی صاحب کے مندرجہ بالا فرمودات مختلف مقامات پر منعقد ہونے والی تقاریر کا حصہ ہیں جنہیں راقم نے خود سنا ہے، البتہ یہ مختلف کتب میں موجود ہیں۔ کتب کی تفصیل حسب ذیل ہے:
۱۔پہلی سالانہ رپورٹ،پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ،اسلا م آبا د ،طبع ،اکتوبر۲۰۰۲،ص:۱۳۳۔۱۴۰
۲۔دینی مدارس میں تعلیم،مرتبہ سلیم منصور خالد،طبع، iiit،اسلا م آبا د،ص:۶۱۔۷۸
روئے گل سیر نہ دیدم و بہار آخر شد
ڈاکٹر حافظ سید عزیز الرحمن
یہ ستمبر ۱۹۹۸ء کی ایک سرد مگر اجلی صبح کا ذکر ہے۔ میں بنوں میں ہوں اور ایک آواز کانوں میں پڑتی ہے: آئیے، فاروقی صاحب! بیٹھیے۔ میں سامنے دیکھتا ہوں تو ایک وجیہ، معتدل القامہ اور روشن شخصیت چھوٹی سی کار میں پچھلی نشست پر بیٹھ کر دروازہ بند کررہی ہے۔ میرا قیاس یہی ہوا کہ یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں۔ برابر میں کھڑے ایک صاحب سے پوچھا تو تصدیق ہوگئی۔ ان کے ساتھ ان کے بہنوئی ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی تھے جو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے رئیس کلیہ علوم اسلامی تھے اور حال ہی ڈائریکٹر شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے منصب سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اسے پہلی ملاقات تو نہیں کہا جاسکتا، پہلی اچٹتی ہوئی، ہلکی سی زیارت ضرور کہا جاسکتا ہے۔ یہ بنوں میں مولانا نصیب علی شاہ رحمہ اللہ کے زیر اہتمام ان کے ادارے المرکز الاسلامی میں دوسری فقہی کانفرنس کا ذکر ہے جس میں راقم بھی مدعو تھا۔ اب تو مولانا نصیب علی شاہ بھی مرحوم ہوچکے۔
ان دنوں ہم اپنے ادارے سے سیرتِ طیبہ پر ایک شش ماہی مجلے کے اجرا کے سلسلے میں سرگرم تھے۔ مشاورت جاری تھی۔ اہل علم سے رابطے ہورہے تھے۔ مجلے کے پہلے شمارے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ راقم نے دوسرے اہل علم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی خط ارسال کیا۔ خلافِ توقع جن چند حضرات نے فوراً جواب دینے کی زحمت کی، ان میں ڈاکٹر صاحب نمایاں تھے اور سب سے مفصل خط آپ ہی کا تھا۔ یہ ۱۹۹۹ء کے اوائل کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بلاتکلف ہمارے خیال اور ارادے کی ستائش کے بعد اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا ذکر کیا اور پوری تیاری کے بعد حالات کا جائزہ لے کر ہی اس میدان میں آنے کی تاکید کی۔ السیرۃ کا پہلا شمارہ جون ۱۹۹۹ء/ ربیع الاوّل میں شائع ہوا۔ ۱۲؍ ربیع الاوّل کو سیرت کانفرنس، اسلام آباد میں شرکت کا اتفاق ہوا تو ’’السیرۃ‘‘ کا نیا شمارہ ساتھ تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ کانفرنس سے فراغت کے بعد اسلامی یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد کے نائب صدر (اکیڈمکس) تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ کانفرنس میں شرکت کے لیے اجتماع گاہ میں پہنچا تو ڈاکٹر صاحب وہاں موجود تھے۔ علم ہوا کہ آج دوسری نشست میں کلیدی خطبہ ڈاکٹر صاحب ہی کا ہے۔ افتتاحی نشست ختم ہوئی تو میں ابتدائی نشستوں پر چلاگیا جہاں ڈاکٹر صاحب قیام فرما تھا۔ چائے کا وقفہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب وہیں تشریف فرما رہے۔ میں سلام کرکے بیٹھ گیا اور ’’السیرۃ‘‘ کا پہلا شمارہ پیش کردیا۔ شمارہ خود راقم کا تعارف تھا۔ شمارہ دیکھ کر فوراً بولے کہ میں نے آپ کو بہت ڈرایا تھا۔ آپ نے ہمت کی، اللہ مبارک کرے۔ اب مسلسل نکالتے رہیے۔ اس وقت تک دادا جان حضرت مولانا سید زوار حسین رحمہ اللہ سے راقم کے تعلق کا ڈاکٹر صاحب کو علم نہ تھا۔ میں نے بتایا تو ڈاکٹر صاحب کے رویے میں اور انسیت آگئی۔ پھر جب تک دوسری نشست کا آغاز نہیں ہوامجھے، وہیں بٹھائے رکھا۔ نہ خود چائے کے لیے گئے، نہ مجھے اس قیمتی نشست کو چھوڑ کر جانا مناسب معلوم ہوا۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات تھی اور اس روز ڈاکٹر صاحب کا کلیدی خطبہ جو عدم برداشت کے قومی و بین الاقوامی رجحانات پر تھا، میرے لیے ڈاکٹر صاحب کو براہِ راست سننے کا پہلا اتفاق تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے متعلق اس نشست میں قائم ہونے والا نقش اس قدر پختہ ہوا کہ پھر ڈاکٹر صاحب کی تقریروں اور تحریروں کا انتظار رہنے لگا اور ایک جستجو سی قائم ہوگئی کہ ان کی چیزیں اہتمام سے پڑھی جائیں اور بالالتزام جمع کی جائیں۔
ڈاکٹر صاحب ان خوش نصیب فضلا میں شامل ہیں جنہوں نے سترہ برس کی عمر میں تدریس کا منصب سنبھال لیا تھا اور اسلامی علوم و فنون کی نمائندہ و چنیدہ کتب کی تدریس ان کی زندگی کا حصہ رہی ۔یوں اکنافِ عالم میں ان سے استفادہ کرنے والے تلامذہ کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں ۔ ڈاکٹر صاحب حافظ قرآن تھے اور رمضان المبارک میں اپنی رہائش گا ہ پر تراویح میں قرآنِ کریم سنانے کا اہتمام فرماتے تھے۔رمضان کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب عام طور پر با وضو رہتے اور فارغ اوقات میں خصوصاً دورانِ سفر آپ کے لبوں پر تلاوتِ قرآن جاری رہتی۔
ڈاکٹر صاحب نہایت جفاکش ،محنتی،کمٹڈ اور دل درد مند رکھنے والے محقق، عالم ،مفکر ،داعی اور فقیہ تھے۔ آپ پاکستان میں اسلامی بینکنگ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں ۔ تکافل کا ابتدائی خاکہ آپ ہی کا تشکیل کردہ ہے جس پر پاکستان سے پہلے بعض عرب ممالک میں عمل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں آئینی اور قانونی معاملات میں اسلامی دفعات کے بھی ماہر سمجھے جاتے تھے۔ جنرل ضیا الحق مرحوم سے لے کرجنرل مشرف تک ہر دور میں حکمران آپ سے اس سلسلے میں مستفید ہوتے رہے،یہ الگ بات ہے کہ حکومتی مزاج ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو کس قدر ہضم کر پایا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ نتائج سے بے پروا ہو کر درد مندی اور خیر خواہی کے جذبے سے ہر حاکم وقت کو صحیح مشوروں سے نوازتے رہے۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس نیک مقصد کے لیے کوئی آئندہ بھی بلائے گا تو میں جانے کو تیار ہوں۔
سود کے خلاف سپریم کورٹ کے مشہور اور تاریخ ساز فیصلے میں بھی ڈاکٹر صاحب بہ حیثیت جج شریعت اپیلٹ بنچ شریک رہے اور اس فیصلے کا بڑا حصہ ڈاکٹر صاحب ہی کا تحریر کردہ تھا۔اس بنچ میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی بھی شامل تھے۔ قادیانی تحریک کے خلاف مسلمانوں کے متفقہ مؤقف کی ترویج و اشاعت اور اس سلسلے میں ہونے والی قانون سازی میں بھی ڈاکٹر صاحب کی ماہرانہ رائے اور تگ و دو شامل رہی۔۸۰ کی دہائی میں جب اس سلسلے کا ایک مقدمہ ساؤتھ افریقہ میں قائم ہوا تو پاکستان کے علما اور قانونی ماہرین کا ایک وفد وہاں کے اہل علم کی دعوت پر معاونت کے لیے گیا،اس وفد میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل تھے اور وہاں عدالت کے روبرو امت مسلمہ کا موقف پیش کرنے کی سعادت ڈاکٹر صاحب کے حصے میں آئی۔ اور بالآخر اس مقدمے میں عالم اسلام کے مؤقف کو غیر مسلم عدالت کے سامنے سرخ روئی حاصل ہوئی۔
ڈاکٹر صاحب انتہائی متدین اور حد درجہ متقی شخص تھے۔ بر س ہا برس کا مشاہدہ ہے کہ سرکاری ودفتری ذمے داریوں میں سرکاری مراعات سے کبھی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا وجود عالم اسلام کے لیے بسا غنیمت تھا۔ بین الاقوامی فورم پر اسلام اور پاکستان کی نمائندگی کا جو سلیقہ ڈاکٹر صاحب کو حاصل تھا، اس کی مثال کم ملے گی۔ پھر علم وفضل اور دینی حمیت وتصلب کے ساتھ ساتھ حسن تکلم وحکمت کی دولت سے آراستہ تھے جس سے وہ ایسے مواقع پر بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔
اس وقت ڈاکٹر صاحب کا جامعۃ الرشید میں ہونے والا خطاب میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے جو چند برس پیش تر دورۂ قضا و تحکیم کے اختتامی روز فرمایا تھا۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کی قضا کی پوری روایت اور اس کا محاکمہ اپنے اسلوب میں پیش کیا تھا۔ یہ خطاب لگ بھگ دو گھنٹے جاری رہا۔ اس کے اختتام پر ملک بھر سے آئے ہوئے مفتیانِ کرام نے متفقہ طور پر اس خطاب کو پورے کورس کا حاصل قرار دیا۔
علومِ اسلامیہ میں ایک عجب وحدت پائی جاتی ہے جو اسے دیگر علوم و فنون سے نمایاں و ممتاز کرتی ہے۔ قرآن کو سنت سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔ فقہ کو حدیث سے جدا نہیں کرسکتے۔ سیرت اور تاریخ باہم پیوست ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہی حال دیگر تمام علوم و فنون کا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر غازی صاحب اس وحدت علوم اسلامی کی نمایاں زندہ، عملی اور نمایندہ مثال تھے۔ آپ سب ہی علوم و فنون سے آشنا تھے، سب سے واقف تھے، سب کے شناور تھے۔ تحریر و تقریر میں ان علوم و فنون کے باہمی تعلق کو ایسے غیرمحسوس انداز میں بیان کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ طرز استدلال اور قوت مشاہدہ، دونوں اس قدر قوی تھیں کہ ایسے نکات آپ تلاش کرلیتے تھے جس کی جانب دوسروں کی نگاہ نہیں جاتی۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب استدلال ملاحظہ کریں تو معلوم ہوتا ہے، سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے اصول فقہ سے استدلال کرتے ہیں جو ان کا خاص اور پسندیدہ موضوع ہے، تعلیم پر بات کرتے ہوئے تاریخ سے مدد لیتے ہیں اور قانونی امور پر بات کرتے ہوئے نفسیات کے نکات استشہاد میں پیش کردیتے ہیں۔ اس قوت استدلال واستشہاد کی معراج خصوصیت کے ساتھ محاضراتِ سیرت اور اس کے بھی دو خطبوں، کلامیاتِ سیرت اور فقہیات سیرت میں نظر آتی ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ پچاس پچاس صفحات کے یہ خطبے ہزار ہزار صفحات کی کتابوں پر بھاری ہیں۔
علم وفضل کے اس تنوع، تعمق اور تبحر کے باوجود مزاج میں ایسا اعتدال اور تواضع تھا کہ باید وشاید۔ دسیوں اہم ترین مناصب پر فائز رہنے کے باوجود، جن میں سے ایک ایک کی تمنا میں ہم جیسے پوری عمر بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی نشست وبرخاست، تحریر وگفتار، رہن سہن اور ملنے جلنے میں نمودونمائش نام کو بھی نہیں تھی۔ تکلف سے کوسوں دور اور تصنع سے یکسر پاک تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے قریبی عزیز انجینئر سید احتشام حسین راوی ہیں کہ وزارت کے زمانے میں ان کے والد کا پشاور میں انتقال ہوا۔ ڈاکٹر صاحب جنازے میں شرکت کے لیے آئے تو اپنی گاڑی اور عملے کو گھر سے فاصلے پر چھوڑدیا۔ فراغت کے بعد دوپہر میں سب آرام کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ایک کمرے میں جگہ بناکر کونے میں لیٹ گئے۔ اب مہمانوں کی کثرت تھی، چھوٹا سا گھر اور جنازے کا موقع۔ کسی ضرورت سے وہ کمرہ خالی کرانا پڑا۔ کسی نے آواز لگائی تو ڈاکٹر صاحب بھی اٹھ گئے اور خاموشی سے دوسری جگہ تلاش کرنے لگے۔ جگہ نظر نہ آئی تو چپ چاپ گھر کے قریب ایک ناپختہ مختصر سی مسجد میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب کے لیے فون آیا تو ان کی تلاش شروع ہوئی۔ نہ ملنے پر کسی نے سوچا کہ قریبی مسجد میں جھانک لیں۔ دیکھا تو مختصر سی مسجد کے کچے صحن میں گرمی کے عالم میں دیوار کے سائے تلے اپنے جوتے سر کے نیچے رکھے مطمئن انداز میں آرام فرما ہیں۔ دیوار کا وہ سایہ نصف آدمی کے لیے ناکافی تھا۔ مسجد کا ہال جو صرف دو صفوں پر مشتمل تھا، بند تھا۔ اس لیے اس کے کچے صحن میں ہی جگہ مل سکی اور اسی پر قناعت کرلی۔
ڈاکٹر صاحب کا دل درد مند تھا جو خصوصاً اُمت مسلمہ کے حالات پر بہت کڑھتا تھا۔ مسلمانوں کی روایتی سستی وکاہلی، کام چوری، کج فہمی اور بدانتظامی پر پریشان رہتے۔ دو ڈھائی برس قبل جب قطر چلے گئے تو خصوصاً عالم عرب کو مزید قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اپنے مشاہدات وتجربات عندالملاقات گفتگو میں بیان کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کہنے لگے، جب میں اسلام آباد میں یونیورسٹی میں تھا تو اپنے عملے کی سستی سے نالاں رہتا تھا، مگر جب سے یہاں آیا ہوں تو علم ہوا ہے کہ سستی کیا ہوتی ہے۔ اب تو مجھے اسلام آباد والے نہایت چست اور انتہائی متحرک محسوس ہونے لگے ہیں۔ عربوں کے روایتی طرزِ زندگی پر اس سے بہتر طنز شاید نہ ہوسکے۔
۲۰۰۸ء میں جون کے آخر میں مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی کانفرنس برائے مکالمہ بین المذاہب منعقد ہورہی تھی۔ میں بھی مکہ مکرمہ میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر سے وہاں تشریف لائے۔ حرم میں ملاقات ہوئی تو بتانے لگے آج مغرب میں جب حرم آنے لگے تو اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ انہیں صحن کعبہ میں خواتین کے لیے مخصوص حصے میں چھوڑنے جارہا تھا کہ ایک مطوعے نے روک لیا۔ کہنے لگا: حرام حرام، ممنوع ممنوع۔ میں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مزید سخت لہجہ اختیا کرلیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں خود اس امر کے حق میں ہوں کہ یہاں خواتین کا مردوں سے اختلاط نہ ہو اور ان کی جگہ مخصوص ہو، مگر اس کے لیے لوگوں کو مطلع تو کرنا چاہیے۔ راتوں رات نت نئے قوانین آجاتے ہیں اور دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان زائرین پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ بتانے لگے کہ کئی بار اعلیٰ ترین حکام کو اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی کہ زائرین کے لیے مختصر ہدایات چند بین الاقوامی زبانوں میں تیار کرکے انہیں یہاں آتے ہی فراہم کردی جائیں تو یہ بدنظمی نہ ہو۔ ملاقات میں تو وہ مان جاتے ہیں، بعد میں عملدرآمد نہیں ہوتا۔
راقم نے جب کبھی زحمت دی تو فوراً حامی بھر لی ۔چاہے کسی نوع کا کام ہو،میں نے کبھی ڈاکٹر صاحب سے کسی کام میں ’’نا‘‘ نہیں سنا۔ ہاں کوئی تجویز ہوئی تو صرف یہ کہا کہ اسے یوں کر لیں۔البتہ ایک بار کسی ٹی وی چینل سے مجھے پیغام ملا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے ہاں پروگراموں میں شرکت کے لیے رضامند کریں۔ میں نے بات کی تو صراحتاً تو منع نہیں کیا، البتہ اس قدر کہا کہ مجھے اس کام سے دور رکھو تو بہتر ہے۔ میں خود اس معاملے میں متردد تھا، سو اصرار نہیں کیااور بات آئی گئی ہو گئی۔
ڈاکٹر صاحب سے آخری ملاقات ان کی وفات سے چند روز قبل کراچی میں ہوئی جب وہ اسٹیٹ بینک کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔راقم کو ایک کام کے سلسلے میںیاد فرمایا۔ میں حاضر ہو گیا۔ جب پہنچا تو میٹنگ ختم ہو چکی تھی اور ڈاکٹر صاحب اےئر پورٹ روانہ ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور اےئر پورٹ تک ان کی معیت حاصل رہی۔قابل ذکر بات یہ ہے کہ واپس پہنچ کر ڈاکٹر صاحب نے راقم کو خط لکھا جو راقم کے نام ڈاکٹر صاحب کا آخری خط ثابت ہوا۔ اس میں انہوں نے نہایت انکساری کے ساتھ معذرت کی کہ میری وجہ سے آپ نے زحمت کی،اللہ اکبر!
ڈاکٹر صاحب مومن کامل اور پکے پاکستانی تھے۔ جب بات نکلتی، پاکستان کی بات آتی، تحریک پاکستان کا ذکر ہوتا، قیام پاکستان کی مشکلات اور تعمیر پاکستان کے پہلے مرحلے کی بات ہوتی تو نہایت تیقن اور بھرپور جذبے کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ ان کے خیالات سے ڈھارس بندھ جاتی، قوت ملتی، تحریک ہوتی اور انسان کو قوتِ عمل اور نیا ولولہ ملتا۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن کر ہی یہ ارادہ ہوا تھا کہ خاص تحریک پاکستان اور قیام پاکستان پر ان کی تفصیلی گفتگو رکھی جائے اور ان سے استفادہ کیا جائے۔ زبانی اجازت بھی لے لی تھی۔ کسی مناسب موقع کا انتظار تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا انتظار ختم ہوا اور وہ عجلت میں اپنے کام سمیٹتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگئے۔ نہایت شاداں وفرحاں، کامیاب وکامراں، مطمئن وآسودہ۔
ہم جیسے دنیا دار یہی لکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات بے وقت تھی۔ ہماری کوتاہ نظر مشیت الٰہی تک کہاں پہنچے اور کیوں کر پہنچے، مگر ڈاکٹر صاحب کا معمول یہ تھا کہ ہم ایسے ناکارہ لوگوں کی دعوت بھی کبھی رد نہیں فرمائی۔ جب کبھی زحمت دی، قبول کی۔ کسی نیک کام کا اعلان ہوا، انہیں ہمیشہ تیار پایا۔ ایسا شخص اپنے رب کے بلاوے پر کیسے تاخیر کرتا؟ نمازِ فجر ادا کی، برکت کے وقت برکتیں سمیٹیں اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوگئے۔
بقا صرف ذاتِ حی وقیوم کے لیے ہے۔ ہاں! ڈاکٹر صاحب کی یاد عرصے تک لو دیتی رہے گی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کیا شخصیت تھے! یہ نقصان کسی ایک کا نہیں، پورے عالم کا نقصان ہے۔ نہ ایسی شخصیات روز روز پیدا ہوتی ہیں، نہ ایسے نقصانات کی تلافی کی صورت ہی نظر آتی ہے۔ اس دنیا میں ایک بار آجانے کے بعد جانے سے کسی کو مفر ہے؟ مگر انسانی فکر چوں کہ محدود ہے، اس لیے ایسے نقصانات میں جو پورے عالم کا نقصان ہو، ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حادثہ بے وقت تھا۔اگر یوں کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب جیسی صاحبِ علم و بصیرت ،صاحبِ تفقہ،متوازن و متواضع اور جدید و قدیم کی جامع شخصیت عالم اسلام میں کم ہو گی تو یہ بیان نہ مبالغے پر مشتمل ہوگا نہ محض عقیدت پر، بلکہ صرف حقیقت پر مبنی ہوگا۔
ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا تنوع ایک تحریر نہیں، مسلسل تحریروں کا تقاضا کرتا ہے۔ یقیناًاہل علم اس جانب توجہ فرمائیں گے۔ خصوصاً ڈاکٹر صاحب کی علمی خدمات پر گفتگو اہل علم کو ہی زیبا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کی اچانک ناگہانی وفات نے ایک سکتہ سا پیدا کردیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اب تک یقین ہی نہیں دلاسکے کہ یہ حادثہ واقعی پیش آچکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی صحت، غیرمعمولی محنت، مضبوط اعصاب، اپنے مشن کے ساتھ نہایت غیرمعمولی وابستگی اور سب سے بڑھ کر عمر، یہ سب عوامل مل کر ہمیں مطمئن کیے ہوئے تھے کہ ابھی تو ڈاکٹر صاحب سے استفادہ جاری رہے گا۔ ابھی تو تادیر ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ افسوس :
روئے گل سیر نہ دیدم وبہار آخر شد
بلکہ پورا شعر ہی حسب حال محسوس ہوتا ہے:
حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد
روئے گل سیر نہ دیدم وبہار آخر شد
ڈاکٹر صاحب سے وابستہ یاد یں بہت سی ہیں۔ ان کی ناگہانی اور الم ناک وفات نے یادوں کے دریچے کھول دیے ہیں، مگر انھی سطور پر ختم کرتا ہوں۔ یہ یادیں امانت ہیں۔حواس کچھ بحال ہوئے تو قدرے ترتیب سے یہ امانت لوٹانے کی کوشش کروں گا۔
یاد خزانہ
ڈاکٹر عامر طاسین
باشعور انسان اپنی زندگی میں ایک عجیب سا تأثر اُس وقت لیتا ہے جب اُس کی ملاقات کسی ایسی علمی شخصیت سے ہو جو کہ اپنی ذاتی زندگی میں ذکر و عبادت کی پابند ی کے ساتھ اس منزل پر پہنچ چکی ہو جہاں فہم وبصیرت کے تقاضے موجود ہوں، جہاں دینی حمیت و بیدارگی کی فکر ظاہر ہو، جہاں خداداد قوت فیصلہ کی صلاحیت اجاگرہو، جہاں تنقیدی سوچ وفکر کے بجائے اصلاحی مزاج جگہ لے لے، جہاں خود نمائی و خودغرضی کے بجائے عاجزی اور انکساری ہو، جہاں علوم وفنون کا بہتا سمندر ہو، جہاں روشن ستارے آپس میں ہر ایک کو اپنی کرنوں سے بلا تمیز رنگ و نسل و مسالک کو منور کرنے کو شش میں سرگرداں ہوں، جہاں کسی کے تند و تیز اورسخت لہجہ پر سکوت اور خاموشی ہو، جہاں چھوٹوں پر شفقت اور محبت کے پھول نچھاور ہوں، جہاں احترام واکرام موجود ہو، جہاں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ فکر نے جمود کے سکوت کوتوڑا ہو، جہاں فکری روش روایت پرستی، روایت پسندی میں پنہا ہو، جہاں فکر وشعور کی ہر منزل پختہ ہو۔ اپنی بے نیازی میں دنیاوی منصب کی منفعت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تدبیر انسانی کو ممیز و معقول کر کے تقدیر الٰہی پر صبر و شکر کرنے والے چند ہی لوگ نظر آتے ہیں اور ان میں ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ کا بھی نام سر فہرست نظر آئے گا۔ آج ایسا انسان دنیا سے چلا گیا جو عصری فقاہت و ذکاوت کا بادشاہ تھا، جس نے وہ فکر دی جس نے عصری تقاضوں پر مبنی مسائل کو ماضی کے فکری جمود سے آزاد کرانے میں دن رات سعی کی اور پھر ایسے مختلف موضوعات پر مبنی محاضرات پیش کیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُن کی زندگی کا بیش قیمت خزانہ تھے اور وہ اپنا سارا علمی خزانہ سرمایے کی طرح لوگوں میں نچھاور کرکے تا ابد اپنی تحریروں میں زندۂ جاوید ہوگیا۔
والد محترمؒ علامہ محمد طاسین کے انتقال کے کچھ دن بعد مجھے ڈاکٹر صاحب نے اسلام آباد سے ٹیلی فون کیا اور نہایت دردمندانہ لہجے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت کی اور یہ کہا کہ بظاہر یہ تو رسمی تعزیت ہے مگر سچ تو ہے کہ میں اپنے ایک استاد سے محروم ہو چکا ہوں۔ میں نے ایسے علما جن میں اجتہادی صلاحیتیں موجودہوں، کم ہی دیکھے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ طاسین کی اجتہادی مسائل پر فکر آمیز تحریریں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ مولانا کے درجات کی بلندی کے ساتھ گھر والوں کے لیے بھی صبر جمیل کی دعاکی۔
والد صاحب ؒ کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی ڈاکٹر صاحب سے کراچی میں رابطہ ہوا اور اس وقت آپ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بنچ کے جج کے منصب پر فائز تھے اور ایک اجلاس میں کراچی تشریف لائے ہوئے تھے۔اس وقت شریعت اپیلیٹ بنچ میں سود کے مسئلے پر بحث وگفتگو جاری تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اسی بنچ میں موجود ہیں۔ ملاقات کی تمنا دل میں تھی کہ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب کا گھر پرٹیلی فون آیا، انتہائی خوشگوار انداز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ محمود غازی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ان کی آواز سن نہایت ہی مسرت ہوئی۔ حال احوال کے بعد والد گرامی ؒ کے وہ مضامین جو کہ اقتصادی موضوعات پر تحریر شدہ تھے، دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔
میں دوسرے دن مقررہ وقت پر سیشن ختم ہونے پر ڈاکٹر صاحب کے چیمبر میں گیا۔ وہاں موجود ایک سپاہی کو آنے کی غرض بتائی۔ اُس نے اندر جاکر ڈاکٹر صاحب کو آگاہ کیا ۔ میں حیرت زدہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب خود دروازے پر آگئے۔ مصافحہ اورمعانقہ کرنے کے بعد بہت محبت سے ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب لے گئے۔ مجھے صوفے پربیٹھنے کو کہا اور خود برابر میں تشریف فرماہو گئے۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے وہ مضامین آگے کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت توجہ سے ہر مضمون کو دیکھتے ہوئے فرماتے کہ اگر مجھے ان مضامین کی نقول دستیاب ہو جائیں تو ممنون رہوں گا۔ میں نے اثبات میں جواب دیا اور وہی اصل مضامین ان کی خدمت پیش کردیے اور آپ نے فوری طور پر ان کی فوٹواسٹیٹ کے لیے ایک صاحب کی ذمہ داری لگائی۔ تب تک چائے آچکی تھی اور ڈاکٹر صاحب مجھے اس بات کی ترغیب فرمارہے تھے کہ مولانا کے بقیہ جتنے بھی مضامین رہ گئے ہیں، انہیں کتابی شکل میں لائیے ۔
ڈاکٹر صاحب اپنے ایک مضمون میں مولانا طاسین کی فکری خوبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
’’اُنہوں نے ایک طرف اپنے خیالات میں خاصی پختگی پیدا کی تھی لیکن اُس کے باوجود اختلاف رائے کو نہ صرف برداشت کرتے تھے بلکہ اُس کا خیر مقدم بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ان تمام لوگوں سے گفتگو کے لیے تیار رہتے تھے جو اُن سے مختلف رائے رکھتے تھے۔ اس سے اُن کے مزاج میں ایک ایسی وسعت اور فکر میں ایسی گہرئی پیدا ہو گئی تھی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔‘‘ (تعمیر افکار، اشاعت خاص بیاد علامہ محمد طاسین، اگست ۲۰۰۶ء، ’’چند یادیں چند تأثرات‘‘، ص ۷۸)
میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم ڈاکٹر صاحب کی مولانا طاسین ؒ کی فکر کے حوالے سے جوخیالات مجتمع تھے، وہ یقیناًسند کی حیثیت رکھتے ہیں اور میرے لیے بھی رہنمائی کا باعث ۔ لہٰذا والد صاحب کے انتقال کے بعد ایسی علمی شخصیات کے ساتھ میرا کسی قدرتعلق خود میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ ان مضامین کی نقول آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے معلوم کیا کہ پڑھائی کہاں تک چل رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ ایم اے اسلامیات کر لیا ہے اور پہلی پو زیشن حاصل کی ہے اور اب پی ایچ ڈی میں بھی داخلہ لے لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جان کر بہت خوش ہوئے اور چند نصیحتوں کے بعد دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ اجلاس کے ختم ہونے کے بعد وقت ہوا تو مجلس علمی(نئی منتقل شدہ جگہ) پر ضرورحاضر ہوں گا۔ میں اجازت لے کر روانہ ہوگیا ۔مجھے اُس وقت سب سے زیادہ خوشی اِس بات کی تھی کہ والد صاحب کے وہ مضامین ڈاکٹر صاحب کے لیے مددگار اور ملکی فیصلے میں کسی درجہ معان ثابت ہوں گے۔
اس کے کچھ عرصے بعد ڈاکٹر صاحب کا اسٹیٹ بنک کے شریعہ بورڈ کے اجلاس میں آنا ہوا۔ ڈاکٹر سید عزیز الرحمن کی وساطت سے پھر ملاقات ہوئی اور انہیں مجلس علمی آنے دعوت دی جسے وقت مقررہ پر قبول کیا۔ جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور لائبریری کو نئے سرے سے دیکھا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور کتاب تأثرات میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ ڈاکٹر صاحب ؒ نے لکھا:
’’الحمد للہ آج کم وبیش بیس سال بعد پھر مجلس علمی میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ اس ادارہ سے میری وا بستگی کم از کم چالیس پینتالیس سال پرانی ہے۔ اس ادارہ کے پاکستانی مؤسس مولانا محمد طاسین مرحوم سے میری ذاتی نیاز مندی ۱۹۷۲ کے لگ بھگ سے تھی جو اُن کی وفات تک جاری رہی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برادر عزیز محترم عامر طاسین کو توفیق، ہمت اور وسائل عطا فرمائے کہ وہ اِس ادارہ کو وطن عزیز کا ایک بہت معتبر علمی ادارہ بنا سکیں‘‘۔ (رجسٹر تأثرات، مجلس علمی کراچی ،۱،۶،۲۰۰۶)
میں والد صاحب کی حالات زندگی پراہل علم احباب کے علمی تأثرات جمع کر نے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور اس حوالے سے سب سے پہلے میں نے سابق چیف جسٹس شرعی عدالت محترم جسٹس تنزیل الرحمن صاحب کے گھر جا کر تأثرات حاصل کیے۔اُس کے بعد میں دیگر اور بھی کئی لوگوں سے رابطہ کیا۔ اُن میں اسلامی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شیر زمان، ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمن، ڈاکٹر سفیر اختراور ڈاکٹر محمود غازی بھی شامل تھے۔ مضامین اور تأثرات حاصل کرنے کے حوا لے سے میرا اسلام آباد جانا ہوا اور ان حضرات سے ملاقات کی۔ڈاکٹر صاحب کے پاس اس وقت غالباً اسلامی یونیورسٹی کے صدر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وفاقی وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری بھی تھی اور یقیناًڈاکٹر صاحب کی مصروفیات حد درجہ بڑھ چکی تھیں۔ میں نے کراچی سے نکلنے سے قبل کئی حضرات سے رابطہ کیا کہ میں اِس غرض سے آنا چاہ رہا ہوں۔ سب نے مجھے ملاقات کا وقت دے دیامگرڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ مختصر یہ کہ میں جب اسلام آباد پہنچا تو دیگر حضرات سے بھی ملاقات ہوتی رہی اور کچھ تأثرات تحریری جمع کر لیے تھے۔ اب وقت تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات کی جائے۔ ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور وقت لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اُنہوں نے مجھے دوسرے ہی دن اپنے دفتر وزارت مذہبی اُمور آنے کا کہہ دیا۔ میں دوسرے دن مقرر وقت پر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ بہت عزت و تکریم وشفقت کے ساتھ باتیں کیں۔ میں نے والد صاحب سے متعلق ان کے علمی تأثرات لکھنے کے بجائے ریکارڈ کر لینے کو ترجیح دی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے طویل گفتگو میں اپنے خیالات ریکارڈ کرائے۔ اس کے بعد میں نے ایک تصویر ساتھ کھنچوانے کی خواہش ظاہرکی، اِس کی بھی تکمیل ہوگئی اور پھرچائے و دیگر لوازمات کے بعد شکریہ کے ساتھ اجازت چاہی۔
میرا یہی ارادہ تھا کہ میں سفر میں ہی ریکارڈ شدہ گفتگو کو قلم بند کر لوں گا۔ جب کراچی واپسی کا ارادہ کیا تو عجیب معاملہ ہوچکا تھا۔ ٹیپ پر وہ گفتگو ریکارڈ تو ضرور ہوئی مگر کسی ٹیکنیکل خرابی کے باعث الفاظ اور جملے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہوگیا۔ میں نے تو بہت مشکل سے ڈاکٹر صاحب کا وقت حاصل کیا تھا اور اب مجھے انہیں آگاہ کرنے میں تأمل رہا کہ کس طرح انہیں بتاؤں۔ ظاہر ہے میری کوتاہی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ خیرجب کراچی پہنچا توکچھ دن بعدبہت ہی شرمندگی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی فون کیا اور انہیں ماجرا سنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اطمینان کے ساتھ یہ جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اگرمولانا طاسین جیسی عظیم علمی شخصیت کے لیے دس مرتبہ بھی کچھ کہنا یا لکھناپڑے تو میرے لیے اعزاز ہوگا ۔ وہ میرے استاد تھے اور میں انہیں اپنا روحانی مربی بھی سمجھتا ہوں۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں ان شاء اللہ خود آپ کو ایک مضمون لکھ کر روانہ کر دوں گا۔ مجھے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ بے فکر رہیں، یہ میری ذمہ داری ہے اور پھر مجھے چند دنوں بعد ڈاکٹر صاحب کا مضمون ٹی سی ایس کے ذریعے موصول ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا وہ مضمون ہم نے ماہنامہ ’’ تعمیر افکار‘‘ کے خاص نمبر (بیاد علامہ طاسین)میں شائع کر دیا۔
اسلام آباد سے واپسی کے بعد غالباً ایک ماہ بعد یہ خبر ملی کہ ڈاکٹر صاحب نے وزارت سے استعفا دے دیا ہے۔ میں نے ٹیلی فون کیا اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد اس خبر کی تصدیق چاہی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بات درست ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر کسی وجہ سے اسلام آباد جانا ہوا اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اُنہوں نے شام کے وقت گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ اس وقت میرے بہنوئی اور بھانجے بھی ساتھ تھے۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب خود ہی چائے و دیگر لوازمات کے ساتھ تواضع کرتے رہے۔ کوئی نوکر نظر نہیں آیا، خود گھر کے اندر سے لاتے اور پیش کرتے رہے۔ کچھ حالات کے پیش نظر گفتگو رہی اور پھر وزارت سے استعفا دینے کے متعلق بھی باتیں ہوتی رہیں۔ یہ بات تو طے شدہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسی علمی شخصیت تھیں کہ وہ جاہ و منصب کے لالچ سے بے بہرہ اور پاک تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر از خود کوئی ذمہ داری عائد کردی تو احسن طریقے سے نبھاتے بھی رہے، مگر جب کسی کادباؤ آتا تو معذرت کر لیتے اور ہر گز قبول نہیں کرتے۔ سفارش اور غیر قانونی کام کو ہمیشہ اپنے مزاج مطابق رّد کر دینے میں عافیت سمجھتے تھے ۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ کسی دباؤ میں آئے بغیر اس منصب ہی کو خیر باد کہہ دیا ۔
اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک دن دعوہ اکیڈمی کراچی ریجنل سینٹر تشریف لائے، وہاں لیکچر کے بعد ایک دو جگہوں پر جانا تھا۔ مجھے ڈاکٹر سید عزیز الرحمن نے مجھے بلا لیا تھا اور اس طرح پھر ڈاکٹر صاحب سے نہ صرف ملاقات ہو گئی بلکہ ان کو ایک دو جگہوں پر لانے اور لے جانے کا بھی شرف حاصل رہا۔ اسی دوران پھر مجلس علمی بھی تشریف لائے اور کچھ مزید نئی تبدیلی پر خوش ہوئے۔ اسی اثنا میں مجلس علمی کے چیف ایگزیکٹو جناب رضا عبد العزیز صاحب بھی موجود تھے اور ان سے ملاقات پر ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ کچھ تھوڑاسا تواضع کا بھی اہتمام تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دعوہ اکیڈمی جانا تھا۔ میں اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ ہی ڈاکٹر سید عزیز الرحمن بھی موجود تھے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراًبعد ائیر پورٹ روانگی تھی۔ وقت بہت کم ہی تھا۔ مجھے ڈاکٹر سید عزیز الرحمن نے کہا کہ کتنی جلدی ہو سکے پہنچنا ہے، کہیں فلائٹ مس نہ ہوجائے۔میں نے کہا بس دیکھیے، ان شاء اللہ فلائٹ مل جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، ڈاکٹر غازی صاحب اور ڈاکٹر سید عزیز الرحمن کو لے ائیر پورٹ کی جانب تیزڈرائیو کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ جہاز روانگی میں بیس منٹ رہ گئے تھے ۔ڈاکٹر صاحب کو الوداع کیا۔ جاتے وقت مجھے کہہ گئے کہ مجھے آپ کی تیز ڈرائیو یاد رہے گی اور شکریہ، جزاک اللہ اور سلام کے بعد ائیر پورٹ کے اندرکی جانب روانہ ہو گئے۔
اس کے بعد بھی جب کبھی ڈاکٹر صاحب کا کراچی آنا ہوتا، بالخصوص ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب اپنے ادارے میں لیکچرز کے لیے مدعو کرتے تو میں ضرور جاتا۔ اس بہانے نہ صرف ملاقات ہوجاتی بلکہ ان کے سیر حاصل علمی بیان سے فائدہ بھی بہت ہوتا۔ اگر کبھی کسی وجہ سے نہ جا سکتا تو دوسرے دن ٹیلی فون آجاتا یا پھر ڈاکٹر سید عزیز الرحمن کے توسط سے اُن کا سلام پہنچ جاتا۔ آخری ملاقات ڈاکٹر صاحب سے اُس وقت ہوئی جب آپ جامعۃ الرشید کے سالانہ کونووکیشن ۲۰۱۰ء میں مدعو تھے۔ آپ کے آخری علمی خطاب سے ہر ایک نے خوب استفادہ کیا۔ مجھے بھی ملاقات کا رسمی موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب کی چونکہ روانگی پہلے سے مقرر تھی، اس لیے صبح اسلام آباد روانہ ہو گئے۔
۲۶ ستمبر کو یہ خبر ملی کہ پیکر علم و عمل، نگاہ جود و سخا، محبت و شفقت کا امین، احترام و اکرام کا منبع اور وسیع علم سے سیراب کرنے والا اور ٹھاٹھیں مارتا ہوعلم کا یہ سمندر دنیا والوں کے لیے اپنے انمول علمی خزانے لٹا کر داعی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کل تک جس نے میرے والد پر مضمون لکھا، آج یہ وقت بھی آئے گا کہ میں اس عظیم علمی شخصیت پر اپنے رسمی تاثرات لکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کے علم کے چشمہ سے ہر ایک کو فیض حاصل کرنے کی تو فیق عطا کرے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ چند تاثرات
محمد عمار خان ناصر
(۳ اکتوبر ۲۰۱۰ء کو الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں اور ۱۹؍ دسمبر ۲۰۱۰ء کو جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کی یاد میں منعقد کی جانے والی تعزیتی نشستوں میں جو گفتگو کی گئی، انھیں یکجا کر کے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ مدیر)
بسم اللہ الرحمان الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد!
آج کی نشست، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، دینی علوم کے ماہر، محقق، اسکالر اور دانشور ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی یادمیں منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمتوں کے مطابق اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ نشست ہمارے پروگرام کے مطابق ڈاکٹر محمود احمد غازی کے افکار اور نتائج فکر سے مستفید ہونے کے لیے منعقد کی جانی تھی۔ اس سے پہلے جنوری ۲۰۰۵ء میں ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور اہل علم کی ایک نشست میں نہایت ہی پرمغز گفتگو فرمائی تھی۔ اس کے بعد پھر کوئی ایسا موقع نہ بن سکا کہ وہ تشریف لاتے۔ رمضان المبارک میں ہم نے ڈاکٹر صاحب ؒ سے گزارش کی کہ وہ ’’دینی مدارس میں قرآن مجید کی تدریس کے تقاضے ‘‘ کے حوالے سے مجوزہ سیمینار میں اپنے نتائج فکر سے حاضرین کو مستفید کرنے کے لیے تشریف لائیں تو کمال عنایت سے انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور اپنی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اتوار کا دن مقرر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے قضا وقدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں ان سے مستفید ہونا مقدر میں نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے اس نشست کو ڈاکٹر صاحب ؒ کی یاد میں ایک تعزیتی نشست میں تبدیل کر دیا۔ اس سلسلہ میں جناب مولانا مفتی محمد زاہد صاحب نے پہلے ہی تشریف لانا تھا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر شہزاد اقبال شام صاحب سے گزارش کی گئی جن کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کافی عرصہ سے رفاقت رہی ہے۔ وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے تشریف لانے والے دوسرے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی شخصیت، تعلیم وتحقیق میں ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی خدمات کے تنوع اور وسعت پر تفصیل کے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی گفتگو کریں گے۔ ویسے بھی مجھے ذاتی طورپر ڈاکٹر صاحب کو زیادہ قریب سے دیکھنے یا ان سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملا، البتہ چند تاثرات کا اظہار میں ضرور کرنا چاہوں گا۔
چند سال قبل دعوہ اکیڈمی اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب کی سادگی اور تواضع کا ایک نمونہ دیکھنے کو ملا۔ دعوہ اکیڈمی نے ’’دینی صحافت‘‘ کے حوالے سے ایک ورک شاپ میں مختلف دانشوروں اور علماء کرام کو بلایا۔ والد صاحب کے ہمراہ میں بھی گیا ہوا تھا۔ پروگرام کے بعد کھانے کی میز پر والد گرامی کھانا کھا رہے تھے کہ اس دوران میں انھیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن پانی میز پر نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے محسوس کر لیا کہ وہ پانی پینا چاہتے ہیں مگر میز پر پانی نہیں ہے۔ اسی وقت فوراً لپک کر گئے اور پانی کا گلاس بھر کر مودبانہ طریقہ سے ان کے سامنے رکھ دیا۔
علمی حوالے سے آپ دیکھیں تو اگر ان کے مقالات، محاضرات اور مضامین کو جمع کیا جائے تو وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی کتابوں کی اشاعت کرنے والے حضرات بتاتے ہیں کہ کبھی بھی ڈاکٹر صاحبؒ نے اپنی لکھی ہوئی تحریروں کو جمع کر کے چھاپنے اور منظر عام پر لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ غالباً وہ اپنی تحریریں اپنے پاس محفوظ رکھنے کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے۔ جب وفاقی شرعی عدالت میں حدود کے مقدمات میں خواتین کی گواہی کا مسئلہ زیر بحث تھا تو ڈاکٹرصاحب ؒ نے بھی اپنا نقطہ نظر لکھ کر عدالت میں پیش کیا کہ حدود کے مقدمات میں خواتین کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ڈاکٹر صاحبؒ سے رابطہ کیا اور گزارش کی کہ مجھے آپ کا لکھا ہوا نقطہ نظر چاہیے، کیونکہ میں ایک بحث میں اس کا حوالہ دینا چاہتا تھا، لیکن وہ تحریر مجھے ڈاکٹر صاحب سے نہیں ملی۔ انھوں نے ’’فکر ونظر‘‘ کے دفتر میں کسی کے ذمے لگایا اور انھوں نے متعلقہ شمارہ تلاش کر کے مجھے بھجوایا۔ اس سے ڈاکٹر صاحبؒ کی علمی تواضع واضح ہوتی ہے۔
اگرچہ ڈاکٹر صاحب ؒ کی دینی تعلیم دیوبندی پس منظر ہوئی اور پھر وہ یونیورسٹی میں چلے گئے، لیکن میرے خیال میں جتنے بھی دینی کام کرنے والے ادارے اور حلقے ہیں، سب ڈاکٹر صاحبؒ کو اپنا اثاثہ سمجھتے تھے۔ ان کی دلچسپی اور مشاغل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر حلقے کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے۔ اپنی تحقیق و تنقید میں کسی خاص مکتبہ فکر کی طرف جھکے ہوئے نہیں تھے اور آزادی سے مسائل پر غور وفکر کر کے رائے قائم کرتے تھے۔ مجھے ڈاکٹر صاحبؒ کے جنازہ پر جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اسلامی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب نے، جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ؒ کے جنازہ پر مجھے ایک بات پر بہت دکھ ہوا۔ جو بزرگ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، غالباً مولانا مشرف علی تھانوی صاحب تھے، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ؒ کی وفات سے علماء دیوبند کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہو رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ؒ کو محدود کیوں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ؒ صرف مسلک علماء دیوبند کا اثاثہ نہیں تھے بلکہ دوسرے مکاتب فکر کے حضرات بھی انھیں اپنا ہی سمجھتے تھے۔
ڈاکٹر صاحب کے خیال میں جو ادارے اور شخصیات کسی بھی نوعیت کی دینی وعلمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، وہ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے تھے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی تھا۔ چنانچہ جنوری ۲۰۰۵ء کی بات ہے۔ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور گفتگو فرمائی تو مجھے اس وقت بھی ان کے ایک جملے پر حیرت ہوئی اور اب بھی حیرت ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ الشریعہ اکادمی جس نوعیت کا کام کر نا چاہ رہی ہے، وہ میرے خیال میں دارالعلوم دیوبند سے بھی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کس ذہنی تناظر میں یہ بات کہی، یہ الگ بات ہے۔ میرے خیال میں یہ بات انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے کی کہ اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں۔ ظاہر ہے کہ اس کام کو معیار اور مقدار کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ صرف حوصلہ افزائی تھی۔
ڈاکٹر صاحب ؒ بڑی پابندی، اہتمام اور دلچسپی کے ساتھ الشریعہ اکادمی اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ رہتے تھے اور گاہے گاہے پیغامات اور خطوط کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ؒ کے مضامین بھی ماہنامہ ’’الشریعہ‘‘ میں چھپتے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست نے ان کے ایک خط کی فوٹو کاپی بھیجی ہے۔ انہوں نے سیرت کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کے محاضرات کی تلخیص اور تخریج کا پروگرام بنایا اور نمونے کے طور پر ایک محاضرے کی تلخیص ڈاکٹر صاحب کو بھیجی تو ڈاکٹر صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کرنے سے پہلے کسی مجلہ میں شائع کرا دیں اور خود ہی ماہنامہ الشریعہ کا نام بھی تجویز فرمایا کہ اس مقصد کے لیے وہ بہتر رہے گا۔
ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ڈاکٹر صاحب کے علمی افادات اور خاص طورپر ان کے سلسلہ محاضرات کا مطالعہ دلچسپی سے کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سلسلہ محاضرات میں ڈاکٹر صاحب نے جن موضوعات کے حوالے سے امت کی راہ نمائی کی ذمہ داری انجام دی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس خاص دائرے میں اس کی اہلیت رکھنے والے حضرات کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قدیم وجدید علوم پر گہری نظر رکھتے تھے، دور جدید کے فکری وتہذیبی مزاج اور نفسیات سے پوری طرح باخبر تھے اور آج کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کو فکر وفلسفہ، تہذیب ومعاشرت، علم وتحقیق اور نظام وقانون کے دائروں میں جن مسائل کا سامنا ہے، وہ وسعت نظر، گہرائی اور بصیرت کے ساتھ ان کا تجزیہ کر سکتے تھے۔ آخری سالوں میں اللہ تعالیٰ نے انھیں مختلف موضوعات پر جس مقبول عام سلسلہ محاضرات کی توفیق ارزانی فرمائی، وہ ان کے غیر معمولی فہم وادراک اور علم وبصیرت کا ایک مظہر ہے۔
اس سلسلہ محاضرات کی پہلی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان سے ایک جامع اور فکری اعتبار سے مربوط ورلڈ ویو سامنے آتا ہے۔ صاحب محاضرات کو اسلام کی فکری ونظریاتی اساسات، اس کے تاریخی کردار اور دنیا کی دوسری نظریاتی اور سیاسی طاقتوں کے ساتھ اسلام کی آویزش کے مختلف مراحل سے بخوبی واقفیت ہے اور وہ اس تاریخی ونظریاتی تناظر میں موجودہ دور میں امت مسلمہ کی صورت حال، اس کو درپیش مسائل ومشکلات اور اقوام عالم کے درمیان اس کے کردار کے مختلف پہلووں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اپنی منصبی ذمہ داری کے لحاظ سے امت مسلمہ پر فکر وفلسفہ، معاشرت، سیاست اور تہذیب وتمدن کی داخلی تشکیل کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اقوام عالم کے ساتھ تعامل اور تفاعل کے زاویے سے معروضی صورت حال کے تقاضے اس سے کیا ہیں، یہ سب پہلو اس ورلڈ ویو میں ملحوظ ہیں اور اس بحث کے اہم گوشوں پر تفصیلی بحث کے ساتھ ساتھ بہت سے جزوی امور پر بھی ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ صاحب محاضرات نے جن موضوعات پر گفتگو کی ہے، وہ اس کے ذہن میں موجود ایک مربوط فکری اسکیم کا حصہ ہیں۔
دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان محاضرات میں گفتگو کا تناظر کتابی نہیں بلکہ واقعی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ معاصر فکری تناظر سے کٹا ہوا نہیں، بلکہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن، حدیث، شریعت، سیرت اور فقہ جیسے خالص علمی اور اکیڈمک نوعیت کے موضوعات میں بھی کلاسیکی اور روایتی علمی بحثیں گفتگو کے پس منظر میں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن مسائل وموضوعات اور نکات بحث کا انتخاب خالصتاً معاصر علمی وفکری اور واقعاتی تناظرمیں ہوا ہے اور صاحب محاضرات نے جدید ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اور اشکالات کے اہم گوشوں پر اپنا تجزیہ تفصیلاً پیش کرنے کے علاوہ بہت سے ذیلی اور جزوی امور پر ایسے اشارا ت بھی بیان کیے ہیں جنھیں بوقت ضرورت اجمال سے تفصیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ محاضرات کی یہ خصوصیت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ صاحب محاضرات کا مطمح نظر درحقیقت نظری علمی بحثوں کے حوالے سے اپنی ترجیحات کا بیان یا نبوغ علمی کا اظہار نہیں، بلکہ اس ہمہ گیر فکری کنفیوژن سے نکلنے میں مدد دینا ہے جس سے اس وقت امت دوچار ہے۔
تیسری اہم خصوصیت مطالعہ اور معلومات کی وہ وسعت ہے جس سے کوئی بھی قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور جو خاص طورپر اس پہلو سے زیادہ قابل رشک اور موجب حیرت ہے کہ یہ خطبات مختصر نوٹس کی مدد سے زیادہ تر حافظے اور یادداشت کی بنیاد پر دیے گئے۔ علمی مآخذ کے حوالہ جات بہت زیادہ نہ ہونے کے باوجود بحثوں کی نوعیت اور تجزیے کے دروبست سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ صاحب محاضرات نے اس موضوع پر قدیم وجدید لٹریچر کا وسیع مطالعہ کیا ہے اور مختلف علمی دائروں میں نشو ونما پانے والی بظاہر الگ الگ بحثوں کا باہمی ربط متعین کرنے کے ضمن میں اس کے ہاں ایک طویل ذہنی عمل ہوا ہے۔ محاضرات سے کلاسیکی علمی ورثے سے عالمانہ واقفیت اور معاصر اہل علم کی ذہنی وفکری کاوشوں اور علمی رجحانات پر گہری نظر، دونوں کی غمازی ہوتی ہے اور اسلامی علوم کے طلبہ اگر مطالعہ اسلام کی وسیع الاطراف علمی روایت کا ایک عمومی تعارف حاصل کرنا چاہیں تو یہ سلسلہ محاضرات اس کے لیے ایک راہ نما ثابت ہو سکتا ہے۔
چوتھی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان محاضرات میں مغربی فکر، اس کی اساسات اور اس کے تہذیبی مزاج پر بھی ایک بھرپور تبصرہ آ گیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فکر اسلامی کے مختلف شعبوں کا مطالعہ دراصل مغربی زاویہ فکر کے ساتھ تقابل کے انداز میں ہو ا ہے اور دونوں فکری نظاموں کی اساسات، امتیازی خصائص اور باہمی تناقضات کی تعیین وتنقیح کا رنگ اس پورے سلسلہ محاضرات پر غالب ہے۔ اس تجزیے میں اعتدال اور توازن پایا جاتا ہے، چنانچہ نہ تو مغرب کے تہذیبی استیلا پر فرسٹریشن اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے اہل مغرب کی ہر بات کی نفی کا رویہ اپنایا گیا ہے اور نہ اس کی تہذیبی چکاچوند اور اقتصادی ترقی سے مرعوب ہو کر اسلام اور امت مسلمہ کے تہذیبی ومزاجی خصوصیات سے دست برداری کا سبق دیا گیا ہے۔ اس گفتگو میں سیاسی اور صحافتی انداز کے سطحی تجزیے اور تبصرے بھی نہیں کیے گئے اور عمرانی علوم، قوموں کی اجتماعی نفسیات اور تہذیبی مطالعے کے معروضی اصولوں کی روشنی میں صورت حال کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔
یہاں ضمناً ایک نقطہ نظر پر تبصرہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک خاص حلقہ فکر کی طرف سے یہ بات بڑے زور وشور سے اٹھائی گئی ہے کہ عالم اسلام کے طول وعرض میں اور خاص طور پر برصغیر میں جن اصحاب علم ودانش نے اسلام اور جدید مغربی فکر وتہذیب کے باہمی تعلق کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کیے، وہ مغربی فکر سے مناسب واقفیت نہیں رکھتے اور اگرچہ اسلام اور اسلامی شریعت وفقہ پر انھیں عبور حاصل ہے، لیکن مغربی فکر وفلسفہ سے کماحقہ واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے معاشرتی، معاشی اور سیاسی اجتہادات میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔
میری طالب علمانہ رائے میں اس زاویہ نظر میں دو چیزوں کو گڈ مڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک چیز ہے وہ خاص ذہنی رو اور وہ مخصوص احساس اور رجحان جو ایک اخلاقی قدر کی صورت اختیار کر کے کسی تہذیب کے رگ وپے میں سرایت کر جاتا، ا س کے ظاہر وباطن کا عنوان بن جاتا اور اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے، جبکہ دوسری چیز ہے اس رجحان اور احساس کی تعبیر وتشریح اور اس کو فکر وفلسفہ کی صورت دینے کے لیے کی جانے والی ذہنی کاوشیں۔ یہ دوسری چیز ظاہر ہے کہ پہلی چیز کے تابع اور اس کی خادم ہے، کیونکہ فلسفیانہ اور نظری بحثیں زیادہ تر یا تو اس مخصوص تہذیبی مزاج کو، جو اس کے مخدوم کا درجہ رکھتا ہے، نفسیاتی سہارا اور مابعد الطبیعیاتی واخلاقی جواز فراہم کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا اس کی کچھ فکری الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اور یا اس تہذیب کی فکری بلند نظری اور تفوق کا تاثر قائم رکھنے کے لیے۔ ان بحثوں کا گہرائی اور باریک بینی سے مطالعہ کرنا یقیناًاس تہذیبی مزاج کے گہرے علمی تجزیے میں بہت مدد دیتا ہے، لیکن جہاں تک اس تہذیب کے بنیادی ذہنی رویے، پیغام اور عملی ترجیحات کا تعلق ہے تو اسے سمجھنے کے لیے اکیڈمک معنوں میں کوئی فلسفی ہونا ضروری نہیں۔ یہ خاص ذہنی رو اپنے سارے مظاہر اورمضمرات کے ساتھ مغرب کی پوری تہذیب کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہے اور انفرادی اخلاقیات سے لے کر سیاست، معیشت، قانون، تہذیب وتمدن اور بین الاقوامی تعلقات تک ہر دائرے میں اس کی ترجیحات سے ہر صاحب نظر واقف ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں مغرب میں فلسفیانہ فکری نظام چاہے کتنے ہی سامنے آئے ہوں، مغربی تہذیب کا جو رخ اور مزاج متعین ہوا ہے، وہ ایک ہی ہے اور اس کے اور اسلام کے مابین پائے جانے والے کسی تضاد کو سمجھنے کی وجدانی صلاحیت اقبال جیسے فلسفی اور کسی دور افتادہ گاؤں میں رہنے والے ایک سادہ صاحب ایمان کو یکساں حاصل ہے۔
پھر یہ بات کہ علماے اسلام کی اجتہادی گمراہیوں کی وجہ اسلام سے ناواقف ہونا نہیں بلکہ مغربی فکر سے ناواقف ہونا ہے، اپنے اندر ایک داخلی تضاد رکھتی ہے۔ متضاد چیزوں کی پہچان کا اصول یہ ہے کہ آدمی ایک چیز سے جتنی گہری واقفیت رکھتا ہوگا، اس کی ضد کو پہچاننے کی صلاحیت بھی اسے اتنی ہی حاصل ہوگی۔ اگر ایک صاحب علم اسلام سے اور اس کی فکری عملی ترجیحات سے فی الواقع کماحقہ واقف ہے تو اس کی مخالف سمت میں جانے والے کسی رجحان سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، اس لیے علماے اسلام نے اگر دور جدید کی کچھ غیر اسلامی چیزوں کو سند جواز دیا ہے تو ان کا جرم دراصل مغربی فکر سے ناواقفیت نہیں بلکہ خود اسلام اور اس کے مزاج سے ناواقفیت قرار پانا چاہیے اور صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ انھوں نے مغرب کے فکری اثرات کے تحت خود اسلام کی ترجیحات کو بدل دینے کی جسارت کی ہے۔
بہرحال ڈاکٹر محمود احمد غازی کے محاضرات دور حاضر میں اسلامی دانش کا ایک بلند پایہ اظہار ہیں اور انھیں اردو زبان کے اعلیٰ اسلامی لٹریچر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی نے وفا نہیں کی، ورنہ خواہش ہوتی ہے کہ محاضرات کا یہ سلسلہ اسی نوعیت کے بعض دوسرے اہم موضوعات تک بھی وسیع ہوتا۔ تعلیم سے متعلق ایک مستقل سلسلہ محاضرات کا وہ ارادہ رکھتے تھے اور شاید تزکیہ نفس اور اخلاقی تربیت کا موضوع بھی ان کے ذہن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے علم وبصیرت سے استفادہ کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کر دے اور اسے ان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین
ڈاکٹر محمود احمد غازی علیہ الرحمۃ
ڈاکٹر حافظ صفوان محمد چوہان
میرے والد پروفیسر عابد صدیق صاحب کا انتقال ۷؍ دسمبر ۲۰۰۰ء کو ہوا۔ وفات سے کچھ دن پہلے اُنھوں نے مجھے ایک خط لکھا جس میں دعوت و تبلیغ کی مرکزی شخصیت حضرت مولانا محمد احمد انصاری صاحب مدظلہ العالی سے متعلق معلومات فراہم کیں۔ میں اُن دنوں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے انگریزی ترجمے (Words & Reflections of Maulana Ilyas) کے آخری حصے پر کام کر رہا تھا جس میں تبلیغ سے متعلق شخصیات کے بارے میں ضروری شخصی معلومات دی گئی ہیں۔ اِس خط کا ایک جملہ تھا: ’’مولانا محمد احمد صاحب مدظلہ ۔۔۔ جامعہ عباسیہ [بہاول پور] میں ۔۔۔ ۱۹۴۲ء میں دورۂ حدیث مکمل کرنے کے بعد نسبت قدیم قائم رکھنے کے لیے دوبارہ دورۂ حدیث کے لیے دارالعلوم دیوبند چلے گئے۔۔۔۔‘‘ ’’نسبت قدیم‘‘ تو بڑی چیز ہے، اِس کے ذروں اور خوشبو کی تلاش میں، میں بھی پھرتا رہا ہوں اور پھرا کرتا ہوں۔ ایسے کئی اسفار میں بھائی سید ذوالکفل مرحوم کی معیت بھی نصیب رہی۔ چنانچہ ہم لوگ ایک بار وقت نکال کر محمد سہیل عمر صاحب اور مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ہاں بھی گئے۔ غازی صاحب سے یہ نسبت میرے اور میرے خاندان کے لیے بڑی سعادت ہے۔ برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ ’’نسبت قدیم‘‘ اردو کے اُن حسین مرکبات میں سے ہے جس کا مناسب انگریزی ترجمہ کم سے کم مجھ سے نہیں ہوسکا۔
محمود غازی صاحب سے اِس نابکار آید کا رابطہ اُن کے ایک خط سے شروع ہونا یاد پڑتا ہے جو اُنھوں نے اِس صدی کے ابتدائی دو تین سالوں میں سہ ماہی ’الزبیر‘ میں چھپنے والے میرے مضمون ’’اردو شاعری میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم‘‘ کو پڑھ کر مجھے لکھا تھا۔ میں تو اُنھیں جانتا تک نہ تھا۔ اُن جیسے مصروف آدمی کا یہ عنایت نامہ اُن کی ذرہ نوازی تھی۔ میں نے جواب بھی دیا اور فون بھی کیا۔ بس یہیں سے اللہ نے تعلق بنا دیا جو بحمداللہ اُن کے دمِ واپسیں تک ٹیلی فون، خط، کتابوں اور رسائل کے تبادلے کی صورت میں قائم رہا۔ وہ اب یاد آتے ہیں تو دل میں ایک کھوہ سی پڑنے لگتی ہے۔ اللہ اُن کے درجات کو بلند فرمائے۔
اِس پہلے خط کے جوابی ٹیلی فون میں (یا شاید کچھ بعد میں) اُنھوں نے مجھ سے میرے والد صاحب کا کلام اور مضامین کا مجموعہ طلب فرمایا۔ میں نے کتب ارسال کیں تو چند روز بعد اُنھوں نے فون پر میرے والد صاحب کے مضمون ’’محسن کاکوروی کی نعتیہ شاعری‘‘ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری خاص دلچسپی کا موضوع ہے۔ اِس مضمون کو کہیں الگ سے چھپوا دیجیے کہ شاید محسن کی شاعری پر بات چیت شروع ہو جائے۔ میں نے اُنھیں بتایا کہ میرے والد صاحب افسوس کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ محسن کی شاعری کو ہر تذکرے سے بھلا دیا گیا ہے حالانکہ وہ صاحب طرز شعرا میں سے ہیں۔ غازی صاحب نے محسن کاکوروی کی نعت گوئی پر اور برعظیم کے اُس وقت کے کلچر پر کئی باتیں بتائیں اور خصوصاً اُن کے ڈکشن پر میرے والد صاحب کے نکات کو سراہا۔ میں نے یہ مضمون ’الزبیر‘ کی کسی قریبی اشاعت میں چھپوایا۔ ڈاکٹر صاحب نے مدیر ’الزبیر‘ ڈاکٹر شاہد حسن رضوی کو اِس کی بابت خط بھی لکھا جو شائع ہوا۔ یہ اُن کا مزاج تھا کہ بس ذرا چھیڑ دیجیے، وہ تاریخ اور ثقافت کی کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ذکر کر دیا کرتے تھے۔
یہ مضمون تعزیتی نوعیت کا ہے، لیکن مناسب ہے کہ اِسی موقع پر غازی صاحب سے اپنی واحد ملاقات کا ذکر کردیا جائے۔ فون پر تو سالہاسال باتیں ہوئیں اور کئی خط بھی آئے اور گئے، لیکن ملاقات کا موقع صرف ایک بار بنا۔ بھائی ذوالکفل اور میں غالباً ۲۰۰۶ء کے اوائل میں کسی وقت اُن کے ہاں گئے تھے۔ رسمی تعارف تو پہلے بھی تھا، لیکن بھائی ذوالکفل کے سعودیہ میں عرب زمین زادوں کو انگریزی پڑھانے کے موضوع سے بات چیت شروع ہوئی اور ذرا ہی دیر میں یہ مجلس کشت زعفران بن گئی۔ غازی صاحب نے بچوں کو بنیادی تعلیم انگریزی میں دینے کے مضمرات کو ذکر کیا اور وہ پرانا لطیفہ سنایا کہ ایک بچے کو My Friend کا مضمون یاد تھا، لیکن امتحان میں My Father پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ اب اُس نے جو لکھا، وہ یوں تھا: I have many fathers but Aslam is my best father. He is my class-fellow...۔ اب جو قہقہہ چھوٹا تو بھائی ذوالکفل نے فرمایا کہ دوسری زبان میں تعلیم دینے کی تو الگ رہی، بنیادی بات معیارِ تعلیم کی ہے۔ وہ لطیفہ بھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک طالب علم نے مضمون فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال رٹ لیا۔ امتحان میں ریل کا سفر پوچھ لیا گیا۔ اب اُس نے ریل گاڑی میں بیٹھنے سے متعلق دو جملے لکھے اور انجن کو خراب کرکے ریل گاڑی کو ایک ویرانے میں لا کھڑا کیا جہاں کھلے میدان میں لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ آگے فٹ بال میچ شروع ہوگیا۔ ابھی ہمیں غازی صاحب کے ساتھ بیٹھے پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ قہقہے تھے کہ کمرے سے باہر بھی سنائی دینے لگے ہوں گے۔
مجھے فون پر ہونے والی گفتگوؤں سے اندازہ تھا کہ وہ اونچی آواز میں ہنسنے والے آدمی نہیں ہیں لیکن یہ ملاقات اِس خیال کی نفی کرگئی۔ دو عالی نسبت، بڑے خاندانی لوگوں کی اِس کھلی ڈلی گفتگو سے میرا جھاکا بھی اتر گیا تھا۔ انگریزی کو نظامِ تعلیم میں بالجبر ٹھونس دینے سے پیدا ہونے والی آدھی تیتیریت آدھی بٹیریت کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ ابھی چند دن پہلے میری چھوٹی بیٹی بریرہ کو سکول میں ایک انگریزی مضمون My School حفظ کرایا گیا جس میں دس جملے تھے۔ تیسرا جملہ تھا: There are many teachers in my school.۔ میں نے اُس جملے میں teachers سے پہلے ایک شرارتی سا اسم صفت لگا کر یاد کرا دیا۔ اُس نے یہ مضمون کلاس میں سنایا تو پورے سکول میں حال حال پڑگئی۔ شکایت ہوئی جو بہت دور تک گئی۔
القصہ غازی صاحب کے مزاج کی یہ جہت ہم پر پہلی ملاقات میں اور پہلی بار کھلی۔ یہاں سے ہماری باتوں کا رخ تخلیقی تحریر اور رٹالائزیشن (Creative Writing & Rote Learning) کی طرف مڑ گیا۔ یہ ذکر ہوا کیا کہ ہمارے موجودہ نظامِ تعلیم سے ایسے پیڑ اُگ رہے ہیں جن کی شاخیں بالکل لنڈ منڈ ہوکر رہ گئی ہیں۔ غازی صاحب نے بصیرت افروز باتیں کیں اور خاص طور سے زور دیا کہ ہم اساتذہ کو پڑھاتے ہوئے جہاں موقع ملے، اپنے مذہبی کلچر اور تاریخ سے مثالیں لانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو مذہب اور مسلک میں فرق رکھنا چاہیے۔ مذہب غیرتِ دینی کا سبق دیتا ہے اور مسلک رواداری کا۔
اِس ملاقات میں اُن کے ایک مضمون پر جو ’الشریعہ‘ میں اُنہی دنوں چھپا تھا، بہت دیر تک گفتگو رہی۔ اِس مضمون کا مرکزی نکتہ یہ تھا کہ مغرب بڑی گہری حکمت عملی کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو (علی الخصوص نان ایشوز میں) مصروف (Engage) رکھتا ہے اور کیا ہماری حکومتیں، زعما، اہل ثروت اور علمی اشرافیہ اور کیا ہمارے عوام151 ہم سب کے سب لوگ مغرب کے فراہم کردہ اور طے کردہ ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے ایک طرح سے مجبورِ محض ہیں۔ میں نے یہ مضمون بھائی عمار ناصر صاحب سے منگواکر کئی دوستوں کو اِی میل اور ڈاک سے بھیجا۔ غازی صاحب کے اِس جملے کی بات اب بھی چلتی رہتی ہے۔ کراچی کے بھائی سلمان سعد خاں نے پچھلے دنوں میڈیا پر سیلاب کی خبریں چلنے پر کہا تھا کہ یہ اُسی وقت تک چلیں گی جب تک مائی باپ کی طرف سے کوئی نیا ایجنڈا میڈیا فلیش کے لیے مہیا نہیں ہوتا۔ بھٹہ مزدور آسیہ کے توہین رسالت کیس کے سامنے آتے ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ آئندہ چند ہفتوں کے لیے دھماچوکڑی کا بندوبست ہوگیا ہے اور جیسے پچھلے سال ایک لڑکی کو کوڑے مارنے والی ویڈیو سے کچھ فوری مقاصد حاصل کیے گئے تھے، اُسی طرح اِس کیس سے وسیع تر اہداف حاصل کیے جائیں گے۔
مغرب والوں کی سپاہِ دانش ہمیں مصروف رکھنے کے لیے ایسے موضوعات سوچتی ہے اور ہمارے لیے پیدا کی جانے والی یہ مصروفیت وقتی یا فوری نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی آنت کی طرح کبھی نہ ختم ہونے والی ازلی و ابدی لم یلد ولم یولد قسم کی ہوتی ہے۔ مثلاً کچھ عرصے سے حجاب اور برقع عالمی میڈیا میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اِس کے نتائج بہت برے نکلیں گے۔ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ یورپ کی بہت سی پارلیمانوں نے حجاب کو خلافِ قانون قرار دے دیا ہے۔ اور ابھی تو یہ آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وقتی لہروں میں بہہ جانے اور انتہائی غیر مستقل کاموں میں کود کر لگ جانے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی حالت سوکھے پتے کی ہے کہ ہوا جہاں چاہے اُڑالے جائے، اِلا ماشاء اللہ۔ اسلام کے لیے ایسے ایسے حسن بن صباح پیدا ہوچکے ہیں کہ خدا ہی خیر کرے۔ میرے منہ میں خاک کہ آسیہ والے کیس کے چڑھتے دریا میں بہہ کر انجامِ کار کہیں توہین رسالت کا قانون سمندر میں نہ اتر جائے۔
اوپر ذکر کی گئی ویڈیو کو دیکھ کر میں نے بھائی ذوالکفل سے کہا تھا کہ یہ لڑکی کوڑے کھاکر جس سہولت سے اٹھی ہے اور کوڑے مارنے والے نے جس سہج سے کوڑے مارے ہیں، اُسے دیکھ کر مجھے فیضؔ کا شعر یاد آتا ہے:
کس قدر پیار سے اے جانِ جہاں رکھا ہے
دل کے رخسار پہ اِس وقت تیری یاد نے ہاتھ
یہ کوڑے ویسے لگے ہیں جیسے دل کے رخسار پہ یاد نے ہاتھ رکھا ہو۔ اِسی بات کو میں نے غازی صاحب سے بھی ذکر کیا اور داد پائی۔ یہ ویڈیو میں نے سب سے پہلے جنابِ افتخار عارف کے ساتھ دیکھی تھی اور دیکھتے ہی کہا تھا کہ اِس میں تین مقامات ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ویڈیو جعلی ہے۔ اِس سلسلے کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب تک تین لڑکیاں یا عورتیں وہ لڑکی ہونے کا دعویٰ کرچکی ہیں جسے کوڑے لگے تھے۔ اِس ویڈیو پر اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل بانکی مون نے ایکشن لیا تھا۔ اُنھیں چاہیے کہ اب پھر ایکشن لیں۔
دعوت و تبلیغ کے تیسرے امیر حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی والدہ کے ماموں زاد بھائی تھے۔ اُن کے اِس رشتے کا ذکر مجھ سے تبلیغ کی مرکزی شوریٰ کے رکن، لارڈ ردرفورڈ کی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کرنے والے واحد مسلمان سائنسدان، پاکستان کے پہلے چیف سائنٹسٹ اور ستارۂ امتیاز ڈاکٹر مظہر محمود قریشی نے کیا تھا۔ میں نے غازی صاحب سے ذکر کیا کہ مجھے حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی سعادت حاصل ہے اور میں نے اُن سے مجمع میں نہیں بلکہ الگ سے بیعت کی تھی۔ گفتگو کا رخ غازی صاحب کے دودمانِ عالی شان کی طرف ہوگیا۔ اُنھوں نے اپنے خاندان سے متعلق کئی باتیں بتائیں۔ بھائی سید ذوالکفل نے اپنے نانا امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اُن کی زندگی کے آخری دنوں میں ہونے والی ملاقات (اپریل ۱۹۴۴ء) کے حوالے سے کچھ باتیں کیں۔ میرے والد صاحب کا ذکر بھی آیا۔ غازی صاحب نے فرمایا کہ مجھے عابد صاحب کے کچھ مضامین سے مولانا جعفر شاہ پھلواری کی ’’اسلام اور موسیقی‘‘ یاد آتی ہے۔ جب ہم واپس ہونے لگے تو مصافحہ کرتے وقت اُنھوں نے اِس بیعت کی نسبت سے میرا ہاتھ چوم لیا۔ میں اِس کیفیت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ آج غازی صاحب کے بھائی محمد الغزالی صاحب سے بھی فون پر بات ہوئی۔ اللہ اُنھیں سلامت رکھے۔
ایک بات اور یاد آئی۔ کچھ سال سے مغرب نے ہمیں ’’بین المذاہب مکالمہ‘‘ نام کی مصروفیت دے رکھی ہے۔ جب اِس منصوبے کا آغاز ہوا تو شہزادہ چارلس پاکستان آیا۔ اُس کے فیصل مسجد کے دورے کے موقع پر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی گئی۔ اِس پر بڑی لے دے ہوئی۔ اخبارات اور انٹرنیٹ پر خبروں سے جب معاملہ خوب پخ گیا تو میں نے براہِ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے غازی صاحب کو فون کیا۔ فرمایا کہ بات اِتنی نہ تھی جتنی کہ بڑھائی گئی۔ چارلس کو تکلیف نہ تھی کہ اذان لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی۔ یہ تو ہمارے چند بے حمیت لوگوں کا Guilty conscious تھا جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ یہ ایک نان ایشو تھا جسے خوامخواہ کھڑا کیا گیا۔ (عرض ہے کہ چارلس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے اُسے ’’لیڈی ڈیانا کا نصف بدتر‘‘ کہا تھا۔ غازی صاحب بہت محظوظ ہوئے۔ اِس مضمون کی فضا ذرا مختلف ہے، لیکن چونکہ بات متعلق ہے اِس لیے ذکر کی۔)
غازی صاحب میڈیا پر آنے کے سخت خلاف تھے۔ میڈیا اُن کے نزدیک ریڈیو یا اخبار کے انٹرویو کی حد تک تو بکراہت جائز تھا، بشرطیکہ اِس میں تصویریں نہ اتاری جائیں۔ تصویر سے اُنھیں انقباض ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ اِس سے روحانیت کا بیڑہ غرق ہوجاتا ہے۔ میڈیا کی نحوستوں کا بتاتے ہوئے اُنھوں نے ایک بار یہ جملہ دوہرایا تو میں نے امِ حبیبہ نام کی خاتون کا ذکر کیا جو ایک مدرسہ پڑھانے والے اللہ والے کی بیٹی ہے اور جسے میڈیا نعتوں کے راستے سے ریڈیو اور پھر ٹی وی پر لایا۔ اب وہ بے پرد نظر آتی ہے۔ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں ٹی وی پر امِ حبیبہ کی نعت آتی تھی تو سکرین پر ایک پھول دکھایا جاتا تھا۔ اب تو نعتوں کے سلسلے میں بھی بڑی ترقی ہوگئی ہے۔ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھے۔ انگریزی محاورے کے الفاظ میں تیز روشنی میں رہنے والے لوگوں کے لیے میڈیا سے جان بچانا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ غازی صاحب مرحوم اپنے عمل سے یہ کرکے دکھا گئے ہیں۔
جن دنوں یورپ میں ساحل پر نہانے کا تین کپڑوں پر مشتمل باپردہ لباس ’’برقنی‘‘ متعارف ہوا، ایک بار فون پر غازی صاحب سے باتوں باتوں میں پردے کا ذکر آیا ۔ میں نے عرض کیا کہ پردے کے بارے میں میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ آیات میں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہر دو کو الگ الگ ہدایات دی ہیں اور اللہ نے مردوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ عورتوں سے پردہ کرائیں۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی، وہ اللہ کی گناہگار ہے نہ کہ اپنے مرد کی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ مرد کے ذمے یہ ضرور ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے رکھے جس میں پردہ کرنا اور شریعت پر چلنا آسان ہو اور اللہ کے حکم سے روگردان ہونا مشکل ہو، کیونکہ اُسے عورتوں پر فوقیت اور افضلیت دی گئی ہے۔ جو عورت پردہ توڑتی ہے، وہ اللہ کا حکم توڑتی ہے اور اِس حکم عدولی پر وہ اللہ کو براہِ راست جوابدہ ہے۔ پھر مجھے اپنا ایک مضمون ’’اسلام میں ادارۂ خاندان اور اُس کی اہمیت‘‘ پڑھنے کو فرمایا۔ یہ مضمون اُن کے محاضرات کے کسی مجموعے میں ہے۔ یہ مضمون بھی میں نے بہت سے دوستوں کو پڑھوایا ہے۔ وہ لوگ جو مذہب کے نام پر خاندانی اور علاقائی روایات کا پرتشدد پرچار کرتے ہیں، اُنھیں چاہیے کہ کھلے ذہن کے ساتھ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے صحابہ علیہم الرضوان کا اِن احکامات پر عمل ملاحظہ فرمائیں۔ صرف یہی ایک نہیں بلکہ محاضرات میں بہت سے مضامین ایسے ہیں جنھیں بار بار پڑھنا چاہیے۔
پچھلے سال بھائی سید ذوالکفل کا انتقال ہوا تو غازی صاحب نے حج کے کچھ روز کے بعد فون کرکے مجھ سے تعزیت کی اور اُن کے حادثے کی تفصیل معلوم کی۔ اُن سے ملاقات کا اور اُن کی خوبیوں کا بہت دیر تک ذکر کرتے رہے۔ فرماتے رہے کہ اُن کے حسن خاتمہ پر رشک آتا ہے۔
۲۴؍ اکتوبر ۲۰۱۰ء کو غازی صاحب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو میں نے سب سے پہلے ششماہی ’’السیرہ‘‘ والے بھائی ڈاکٹر سید عزیزالرحمن سے اور پھر بھائی عمار ناصر سے تعزیت کی۔ مجھے بھائی عزیزالرحمن کے غم کا کچھ اندازہ تھا۔ ۱۷؍ جولائی ۲۰۱۰ء کو یونی کیرئنز انٹرنیشنل نے جامعہ کراچی میں اردو لغت بورڈ کی ’’اردو لغت (تاریخی اصول پر)‘‘ کی تکمیل پر تقریب سپاس منعقد کی تھی جس میں مجھے بھی بلایا گیا۔ اگلے روز دعوۃ ریجنل اکادمی کراچی میں غازی صاحب کا لیکچر تھا جس کے لیے بھائی عزیزالرحمن نے مجھے دعوت دی۔ اُن کا فون آیا تو میں اُس وقت ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کے یہاں سے ہوائی اڈے کی طرف نکل رہا تھا، اِس لیے حاضر نہ ہوسکا اور اِس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اِس کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ بھائی عزیزالرحمن نے غازی صاحب پر لکھے اپنے مضمون بھی مجھے ارسال فرمائے۔
فون پر باتوں میں، میں نے غازی صاحب سے کسی کی غیبت نہیں سنی اور نہ اُنھیں کسی پر تبصرہ کرتے پایا۔ کسی کے بارے میں بات کرتے تو ہمیشہ بھلائیوں کا تذکرہ کرتے۔ نماز کے نہایت سختی سے پابند تھے۔ دنیا کی چیزوں کے بارے میں للچاہٹ اُن میں نہ تھی۔ بے حد نرم دل تھے۔ ۸؍ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو زلزلہ آیا تو میں ہری پور سے ایبٹ آباد، گڑھی حبیب اللہ، بالاکوٹ اور مظفر آباد گیا۔ مجھ سے وہاں کے حالات سنے تو باقاعدہ روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ علم کے ساتھ تقویٰ اور فروتنی، بڑے عہدے کے ساتھ انکسار، تونگری کے ساتھ سادگی، تصنع سے کوسوں دوری151 یہ سب صفاتِ حمیدہ اُن کی ذات میں بڑے احسن طریقے سے جمع ہوگئی تھیں۔
غازی صاحب سے فون پر استفسارات اور معلومات کے تبادلے کی اجازت مجھے حاصل تھی۔ ہر سوال کا جواب ہمیشہ بہت تفصیل سے اور نواحی معلومات کے ساتھ ملتا۔ بعض اوقات حوالہ دیکھ کر بتاتے۔ اِنٹرنیٹ کی ایک سائٹ پر کسی نے قرآنِ پاک کے موجودہ متن کو ناقابل اعتبار بتانے کے لیے نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ صفحات کے عکس رکھے اور اِی میلوں کے سیلاب کے ذریعے لوگوں کو اِس بحث میں الجھایا کہ تقابلی مطالعہ کرکے دیکھ لیں کہ آج جو قرآن پڑھا جارہا ہے، وہ متذکرہ نسخے سے مختلف ہے۔ میں نے ایک ایسی اِی میل اور کچھ صفحات کا پرنٹ آؤٹ غازی صاحب اور عبدالجبار شاکر صاحب کو بھیجا۔ غازی صاحب نے اِس پر بہت افسوس کا اظہار کیا کہ یہ خالص علمی بحث ہے، اِسے عوام میں چلانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پھر اِس سائٹ کے کرتا دھرتا سے بات کرنے، سمجھانے بجھانے اور اِسے بند کرانے تک کی ساری کارروائی میں اُنھوں نے فعال کردار ادا کیا۔ یہ نیکی بھی اُن کے توشے میں ہے۔ لیکن فون پر کیے گئے استفسارات میں سے دو باتیں تشنہ رہ گئیں۔ ایک بار میں نے قرآنِ پاک میں موجود وقوف کی صورتوں کے بارے میں دریافت کیا کہ مثلاً وقف لازم، وقف منزل، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وقف جبریل کی تو سمجھ آتی ہے، یہ وقفِ غفران کیا ہے؟ اِسی طرح قرآنِ پاک کو تیس سپاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ فرمایا کہ ابھی ذہن میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ یاد پڑتا ہے کہ اِن باتوں کا کبھی نظر سے گزر ہوا ہو۔ کسی وقت میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ یہاں اِن دونوں باتوں کو اِس لیے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی صاحب جانتے ہوں تو مجھے ضرور بتا دیں۔
غازی صاحب سے رابطہ ہوتے ہی الشریعہ کا حوالہ ازخود درمیان میں آگیا۔ راقم کے نزدیک الشریعہ کی مثال ایک طرح کے اسلامی ہائیڈ پارک کی ہے۔ میں نے بڑی مدت سے ایسے مولوی صاحبان نہیں دیکھے تھے جو مسلمان کے مسلمان سے اختلاف کو اسلام کا اختلاف نہ سمجھتے ہوں۔ اللہ کے ایسے بندے مجھے تبلیغ والوں میں نظر آئے، پھر عطاء المحسن شاہ صاحب اور سید محمد ذوالکفل بخاری، اور اب مولانا زاہدالراشدی اور اُن کا الشریعہ۔ الشریعہ ایک تحریک ہے جس نے مختلف الخیال مسلمانوں کو اپنا اپنا نقطۂ نظر برقرار رکھتے ہوئے باہم گفتگو کا موقع، سلیقہ اور حوصلہ دیا ہے۔ الشریعہ کے بارے میں یہی بات غازی صاحب بھی کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے اُن کے ایک خط کے آخری جملے پر یہ تحریر ختم کرتا ہوں۔
’’الشریعہ‘‘ کے بارہ میں میرے تاثرات بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں۔ اس کا سارا کریڈٹ مولانا زاہدالراشدی صاحب کو جاتا ہے۔‘‘
یہ مضمون صرف حافظے سے لکھا ہے۔ ممکن ہے کہ ذکر کی گئی کوئی بات اپنے محل سے ذرا آگے یا پیچھے ہوگئی ہو، لیکن اِس سے مطالب پر اِن شاء اللہ کوئی زد نہیں آتی۔)
اتوار: ۱۹/ دسمبر ۲۰۱۰ء
مطابق: ۱۲/ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ
ڈاکٹر غازیؒ ۔ چند یادداشتیں
محمد الیاس ڈار
صبح سویرے میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہمارے ایک دوست سید قمر مصطفی شاہ کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز نے خبر دی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمیں چھوڑ گئے۔ میں لاہور میں تھا۔ جنازہ میں شریک نہ ہو سکنے کا افسوس ہوا۔ کئی دن تک یقین نہ آیاکہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، بلکہ اب تک یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ کئی ایسے دوست جو زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملے، مجھ سے افسوس کا اظہار کرتے رہے جیسے میرا کوئی عزیز رخصت ہو گیا ہے۔ میں اپنے پروگراموں کے لیے جہاں جہاں بھی گیا، ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کرتا رہا۔
وزارت صنعت وپیداوار سے وزارت مذہبی امور میں بطور جائنٹ سیکرٹری میرے تبادلے سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب وزارت کو خیر باد کہہ چکے تھے، مگران کی خوشگوار یادیں وزارت کے ماحول میں رچی بسی تھیں۔ سید قمر مصطفی شاہ ان کے سیکرٹری رہے، مگر ان سے وہ نہایت قریبی دوست اور گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے ملتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ شاہ صاحب غازی صاحبؒ کے جانے کے بعد وزارت خارجہ میں واپس جانے کی بجائے وزارت مذہبی امورمیں رہ گئے اور زکوٰۃ ونگ میں میرے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری رہے۔ جس محبت سے وہ ڈاکٹر صاحب ؒ کی باتیں بتاتے، اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کس قدر اپنائیت اور برابری کا سلوک کرتے تھے۔
وزارت کے چھوٹے ملازم بھی ان کا ذکر نہایت محبت اور احترام سے کرتے۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی ہر چھوٹے بڑے ملازم کو بڑے احترام سے ملتے اور سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ہمیشہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے۔ چونکہ حافظ قرآن تھے، اس لیے پورا راستہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ ان کے اور ان کے بھائی ڈاکٹر محمد الغزالی کے اکثر بچے حافظ قرآن ہیں۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں الگ الگ حصوں میں رہتے تھے۔ انہوں نے بچوں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ ہرمہمان خواہ وہ دفتر کا ڈرائیور یا نائب قاصد ہی کیوں نہ ہو، بچے اس سے احترام سے پیش آتے۔ اگرچہ اکثر سوٹ کا استعمال بھی کرتے تھے، لیکن سادہ لباس کو پسند کرتے تھے۔ کھانا بہت سادہ تناول کرتے اور مرغن کھانے پسند نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں قریب سے دیکھا، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی عادات بے حد درویشانہ تھیں۔ وہ دین کو صرف بیان نہیں کرتے تھے بلکہ عالم باعمل بھی تھے۔ کسر نفسی کا یہ عالم تھا کہ اکثر مہمانوں کے جوتے سیدھے کر دیتے تھے۔ بعض اوقات تو یونیورسٹی یا وزارت کا کوئی معمولی ملازم اگر ملنے جاتا وہ شرمندہ ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب ؒ اس کے جوتے اٹھا کر سامنے رکھ رہے ہوتے۔ کسی صاحب نے بتایا کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر ہونے کے زمانے میں اپنی ہی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو کہتے کہ ڈاکٹر صاحب! مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھاکہ اچھے لوگوں سے صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔
ڈاکٹر صاحب ؒ نے وزارت اس وقت چھوڑی جب ایک متکبر آمر اپنی تمام رعونتوں کے ساتھ موجود تھا اور اس کے جانے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں لوگ ہر ذلت سہتے ہیں، لیکن استعفا دینے کا نام نہیں لیتے۔ قمر مصطفی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ یہ بات ذہن میں لے کر آئے تھے کہ دین اورملک کی کوئی خدمت کر سکیں، لیکن جب ان کو محسوس ہوا کہ سارے کا سارا ٹولہ کسی اور سانچے میں ڈھلا ہوا ہے تو انہوں نے وزارت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ مگر جب تک وزارت میں رہے، شب وروز اپنے فرائض کی بجاآوری میں لگے رہے اور سیاسی وزرا جو کام کئی سالوں میں نہیں کرتے، وہ چند ماہ میں کر گئے۔ زکوٰۃ کی بہتری کے لیے کئی کنونشن کیے، نئی زکوۃ کمیٹیاں بنوائیں، نئی زکوٰۃ اسکیمیں شروع کیں۔ حج وفد میں گئے تو اکیلے گلیوں اور محلوں میں گھوم پھر کر حاجیوں کی مشکلات حل کرنے کا سوچتے رہے۔ سعودی حج منسٹر سے تفصیلی ملاقات کی، کئی ملکوں کے حج وفود سے ملاقاتیں کیں۔ مدارس کے متعلق دین بیزار جرنیلوں سے اعتراف کروایا کہ ہمارے مدارس دنیا کی سب سے بڑی تعلیمی این جی او ز ہیں اور نہایت مفید خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ چونکہ خود دینی مدرسہ کے فارغ التحصیل تھے، اس لیے مدارس کی خدمات کو نمایاں کرنے میں ہر وقت کوشاں رہے۔ علما اور وفاق المدارس ؍ تنظیمات المدارس کے ذمہ داروں سے ملنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مختلف مسالک کے علما کے پاس حاضر ہو کر ان کا نقطہ نظر معلوم کرتے اور بہتری کی تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کرتے۔ مختلف دینی معاملات میں آخر وقت تک کابینہ اور حکومت کی رہنمائی کرتے رہے۔
ان کی دیانت کا یہ عالم تھا کہ آخری دن روانہ ہوتے وقت انہوں نے دفتر کی گاڑی بھی استعمال نہیں کی بلکہ گھر سے اپنی گاڑی منگوائی۔ دفتر کی اسٹیشنری انتہائی کفایت سے استعمال کرتے تھے۔ مثلاً استعمال شدہ کاغذوں کے پچھلے حصے کا رف کاغذ کے طور پر استعمال کرتے۔ فون کا بل ایک سیکشن افسر کے بل سے بھی کم ہوتا۔ وزارت کی مراعات ہر گز استعمال نہیں کرتے تھے۔ وزیروں کے لیے مختص رہائش گاہ کی بجائے اپنے اور اپنے بھائی کے زیر استعمال چھوٹے سے گھر میں رہتے رہے۔
وزارت کی فائلوں میں ان کا ایک تفصیلی خط پڑھنے کو ملا جو انہوں نے صوبائی گورنروں کو عشر نافذ کرنے کے لیے لکھا تھا۔ مجھے بتایا گیاکہ یہ خط لکھنے کے بعد وہ خود بھی گورنروں سے ملنے گئے، لیکن جو فضول دلائل زرعی ٹیکس سے بچنے کے لیے دیے جاتے ہیں، ویسے ہی عشر کے سلسلہ میں دیے گئے۔ ملک میں بے شمار دوسرے قوانین کی طرح زکوٰۃ وعشر کا قانون موجود ہے، مگر قانون نافذ کرنے والوں کی بدنیتی اس ملک کا سب سے بڑا روگ ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ شریعت کے نفاذ کی بات ہو تو مغربیت کے پاکستانی اسیروں سے لے کر پورے مغرب اور امریکہ میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ہماری دینی سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کے آئین اور قوانین میں اتنا زیادہ اسلامی مواد پہلے سے ہی موجود ہے کہ اس کا نفاذ شریعت ہی کا نفاذ ہوگا او ر اس کے نافذ کرنے کے مطالبہ پر رگیں پھڑکنے کا مظاہرہ بھی کم ہوگا، کیونکہ اس طرح ہم آئین اور قانون کے نفاذ کے مطالبے سے بے دین طبقے کی بدنیتی نمایاں کر رہے ہوں گے اور وہ بھی ان کے اپنے میدان فکر میں۔
وزارت میں مجھے زکوٰۃ سے حج ونگ کا انچارج بنا دیا گیا تواسی دوران دعوت ونگ کے جائنٹ سیکرٹری رخصت پر چلے گئے۔ ان کاکام بھی اضافی طور پر میرے سپرد ہوا۔ اسی ونگ میں رویت ہلال کے سلسلہ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں مرکزی اور صوبائی رویت ہلال کمیٹیوں کے سرکردہ افراد، متعلقہ محکموں کے سرکاری افسران اور خصوصی دعوت پر ڈاکٹر صاحب شریک ہوئے۔ وزیر مذہبی امور صدارت کر رہے تھے کہ انہیں اور سیکرٹری مذہبی امور کو وزیر اعظم ہاؤس سے فوری حاضر ہونے کا بلاوا آ گیا۔انہوں نے میٹنگ جاری رکھنے کا کہا۔ کافی حضرات کے دلائل سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب ؒ نے کہا کہ انہیں کسی اور جگہ جانا ہے، اس لیے اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ان کے لیے آسانی رہے گی۔ ان کی سادگی، دوسروں کے لیے احترام اور موثر خطاب آج بھی میرے احساسات میں موجود ہے۔ انہوں نے تمام معاملے کے دینی اور تکنیکی پہلوؤں کو جس انداز سے بیان کیا، اگر ہمارے بھائیوں میں وسعت قلبی ہوتی تو رویت ہلال کے اختلافات ختم کر چکے ہوتے۔
اسلامی یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر طفیل صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ؒ کو ان کی زندگی کے آخری سالوں میں اعلیٰ انتظامی عہدوں کی پیش کش ہوئیں مگر انہوں نے صرف پی ایچ ڈی کے طلبہ کو پڑھانے اورعلمی کام کرنے کو ترجیح دی۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں شمولیت سے پہلے میری اطلاع کے مطابق آپ قطر اور ملائشیا کی یونیورسٹیوں کے نصاب مرتب کرنے میں مصروف رہے۔ آخر اس درجہ کے اسکالر ہم کہاں سے لائیں گے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر یکساں مقبول ہوں۔ اس کے باوجود انکساری کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے بڑے سب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد الغزالی، جو خود اعلیٰ پائے کے اسکالر اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بنچ کے جج ہیں، ڈاکٹر انیس احمد کے بقول نجی محفلوں میں ڈاکٹر غازی سے بھی چھیڑ چھاڑ سے پرہیز نہ کرتے، لیکن ڈاکٹر غازی صاحبؒ کبھی اپنے بڑے ہونے کا حق استعمال نہ کرتے بلکہ ان کی خوش مزاجی سے محظوظ ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب! اب آپ کس کو لطیفے سنائیں گے اور اس پایے کا بھائی کہاں سے تلاش کریں گے؟ ہمارے جیسے لوگ جو ڈاکٹر غازی سے بہت کم ملے، اپنے دل میں ان کی جدائی کا غم آج تک محسوس کرتے ہیں مگر دونوں بھائی تو ایک ہی مکان کے دو حصوں میں اکٹھے رہتے تھے۔ آخروہ اوران کے بچے کس حال میں ہوں گے؟ ہم کمزور بندوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔
وزارت مذہبی امور میں ان کاایک اہم کام تین ماڈل دینی مدارس کاقیام تھا۔ ان مدارس کے سلسلہ میں ڈاکٹر غازی صاحب کا ذہن پڑھنے کے لیے انہی کی تحریر کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ الشریعہ اکادمی کے زیر اہتمام ایک لیکچر میں دینی مدارس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا:
’’نہ وسائل دستیاب تھے، نہ حکومتی سرپرستی دستیاب تھی اور نہ وہاں کے فارغ شدہ حضرات کے لیے قیادت کے مناصب موجود تھے۔ معاشرہ ان کی قیادت کو ماننے اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی رہنمائی مسجد اور مدرسہ کے خاص دائرے تک محدود تھی، اس لیے انہو ں نے جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا اور جتنا دین موجود ہے، انہی کی کاوش سے موجود ہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دین موجود ہے اس کو زندگی کے روزمرہ معاملات سے relate کیا جائے اور اس کو معاشرے میں فعال قائدانہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اہل دین کے پاس دینی علوم کا تخصص بھی موجود ہو اور جس دنیا اور جس معاشرے میں انہیں قیادت فراہم کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی قائدانہ اور ناقدانہ واقفیت انہیں حاصل ہو۔‘‘ (دینی مدارس اور عصر حاضر: مرتب شبیر احمد میواتی، ص ۱۴۷)
انہوں نے ڈاکٹر ایس ایم زمان کے ساتھ مل کر ایک سیٹ اپ قائم کیا اور ماڈل دینی مدارس کے لیے جدوجہداور قدیم علوم پر مشتمل ایک نہایت عمدہ نصاب مرتب کیا۔ میرے پاس حج ونگ کی ذمہ داری تھی اور مدارس سے متعلقہ جائنٹ سیکرٹری جو پولیس کے ڈی آئی جی ہونے کے باوجود بیوروکریسی کے غلط رویوں سے بچے ہوئے تھے اور اپنی مرضی سے اس وزارت میںآئے تھے ، انہوں نے تجویز کیا کہ مجھے ماڈل دینی مدرسہ، اسلام آباد کے پرنسپل کا اضافی چارج دے دیا جائے۔ چند ہفتوں کے بعد وزیر مذہبی امور ایک یورپی وفد کے ساتھ اس مدرسہ کے دورے پر آئے۔ انہوں نے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھی اور کہا کہ کراچی اور سکھر والے مدارس بھی میرے زیر نگرانی دے دیے جائیں۔ اس طرح مجھے تینوں ماڈل دینی مدارس کا مہتمم بنا دیا گیا۔ ایک سال کے اندر اندر ان مدارس کے سٹاف کو متحرک کرکے ہم نے ان کی حالت اس طرح بدل دی کہ ہر طرف سے ’’ بند کرو‘‘ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں ۔ طلبہ وطالبات کی تعداد دوسو سے بڑھ کر ایک ہزار ہو گئی۔ غریب طلبہ کے لیے زکوٰۃ فنڈ سے وظائف مقرر کیے گئے۔ امتحانات کا ایک نظام وضع کیا گیا اور ان کو امتحانات کے لیے اسلامی یونیورسٹی سے منسلک کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خبریں ڈاکٹر صاحب ؒ تک بھی پہنچتی رہیں اور خوش ہوتے رہے۔
ایک دن صاحبزادہ ڈاکٹر ساجدالرحمن (موجودہ ڈائریکٹر جنرل دعوہ اکیڈمی) کا فون آیا کہ وہ سیرت پر ڈاکٹر غازی صاحب کے محاضرات کروا رہے ہیں اورمجھے اس میں شامل ہوناچاہیے۔ باوجود حج کی انتظامی ذمہ داریوں کے ، میں نے بارہ میں سے آٹھ نو محاضرات میں شرکت کی۔ اس دوران چائے کی میز پر صاحبزادہ صاحب نے میرا تعارف کروایا توبہت خوش ہوئے ۔ مدارس کے حوالے سے وہ میرے کام سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا: ڈار صاحب ! کم از کم تین ماڈل دینی مدارس اور قائم کر دیں۔ آپ اس وزارت سے چلے گئے تو یہ کام رہ جائے گا۔ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ تقریباً دو سال ماڈل دینی مدارس کی خدمت کرنے کے بعد میرا تبادلہ ہوگیا اور مجھے ایک تربیتی ادارے کا ڈائریکٹر جنرل بنادیا گیا۔
ڈاکٹر صاحبؒ کے قرآن، حدیث، سیرت، فقہ، شریعت اور معیشت وتجارت پر چھ محاضرات شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے تفصیلی تعارف کے لیے تو ایک الگ مضمون کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات جس کا تذکرہ ضروری ہے اور ہمارے علما اور سکالرز کی رہنمائی کے لیے بہت اہم ہے، وہ ان محاضرات کی ہر مکتبہ فکر میں مقبولیت ہے۔ مختلف مسالک کے علما کے پاس ان کی کوئی نہ کوئی جلد میں نے خود دیکھی ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب ؒ کے نزدیک قرآن وسنت اور دین کی سربلندی بنیادی اہمیت کی حامل تھی اور مسلکی اور فروعی باتوں کی حیثیت ثانوی تھی۔ ان کے ذہن میں عقیدہ وایمانیات او ر تزکیہ واحسان سمیت کچھ اور موضوعات پر بھی محاضرات کا نقشہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر صرف ان محاضرات کے مواد ہی کو دیکھا جائے تو ان کے علم وفکر کی وسعتیں نظر آتی ہیں، لیکن انہوں نے تمام عمر علم کی خدمت کی اورایک عظیم علمی ذخیرہ اہل ذوق کی تسکین کے لیے چھوڑا ہے۔ ان کی تقریر وتحریر یکساں پر تاثیر تھیں۔ علم دین کے لیے ان کی یکسوئی اور قدیم وجدید مسائل سے ان کی آگاہی ان کی کثیرالجہات شخصیت کی آئینہ دار ہیں۔
ہم نے دعوت فاؤنڈیشن پاکستان کا بیڑہ اٹھایا تو ہمارے ذہن میں کام کا یہ نقشہ تھا کہ مختلف مسالک اور دینی جماعتوں کی نمایاں شخصیات کو اس کے تعلیمی بورڈ میں شامل کیا جائے تاکہ اس کے پروگراموں سے استفادہ کرنے والوں کے ذہن میں کوئی جھجک نہ رہے۔ اس کے تعلیمی پروگراموں کا نصاب قدیم وجدید مصنفین کی کاوشوں پرمشتمل ہو، کم فرصت والے خواتین وحضرات کے لیے ایک باسہولت پروگرام ہو اور گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کا بندوبست ہو۔ کام کے آغاز کے وقت ڈاکٹر صاحب ؒ کا نام ہمارے ذہن میں تھا لیکن جب بھی رابطہ کیا تو وہ بیرون ملک ہوتے تھے۔ جب وہ شریعت کورٹ کے جج بن گئے تو ہم نے سوچا کہ اب ان کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونا مشکل ہوگا۔ گذشتہ شعبان میں گوجرانوالہ میں علامہ زاہد الراشدی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ دعوت فاؤنڈیشن کے تعلیمی بورڈ کی رکنیت قبول فرمالیں۔ انہوں نے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا جس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں۔ اس حاضری کے دوران انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر غازی کو بھی اس میں ضرور شامل کریں۔ گذشتہ رمضان میں سیدقمر مصطفی شاہ کے ساتھ ان کے گھر پر حاضر ہو ا تو وہ نہایت خندہ پیشانی سے ملے۔ ہمارے پروگرام کا طویل ڈرافٹ اور ۷۵ کتب پر مشتمل دو ضمیمہ جات انہوں نے ہمارے سامنے نہایت توجہ سے پڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے پروگرام کی اتنی تعریف کی اور اتنی دعائیں دیں کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا ۔ بعدازاں انہوں نے ہرقسم کے تعاون کا یقین دلایا اور بے شمار نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیا۔ میں نے ضمناً عرض کیا کہ اگلے محاضرات دعوت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر ہونے چاہئیں تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ نہیں، اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ،جتنی دفعہ بھی آپ کہیں گے اور جہاں بھی کہیں گے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ان کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ایک مشترکہ جاننے والے بزرگ عیدا لفطر کے موقعہ پر عید گاہ میں ان سے ملے اور دعوۃ فاؤنڈیشن سے تعاون کے لیے کہا توانہوں نے فرمایا کہ میری طرف سے ڈار صاحب کو کہیں کہ وہ ایک میٹنگ بلائیں تاکہ ہم سب بتا سکیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہم دعوۃ فاؤنڈیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ان کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور پھر ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ ڈاکٹر صاحب !اس سب کچھ کے لیے ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ہم آپ کی دعاؤں اور تمناؤں کی آغوش میں ہیں۔
ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی اس شاندار زندگی سے ایک ایسی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں جہاں فرشتے ان کواہلاً وسہلاً مرحبا کہہ رہے ہیں، رب کے انوار ان کااحاطہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے شایان شان ان کا اکرام ہو رہا ہوگا۔ ان کی یہ مختصر زندگی ، ایک طویل اور پرمسرت زندگی کا نقطہ آغاز تھی۔وہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں جو خالدین فیہا کی تصویر ہے۔ بقول علامہ اقبال ؒ
تو اسے پیمانہ امروز وفردا سے نہ ناپ
جاوداں، پیہم رواں، ہردم جواں ہے زندگی
ایک ہمہ جہت شخصیت
ضمیر اختر خان
اللہ تعالیٰ نے بشمول انسان کے تمام مخلوقات کے لیے موت کے حوالے سے اپنا ضابطہ قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے: کل من علیھا فان (سورۃالرحمن:۲۶) کل نفس ذائقۃ الموت (سورۃ آل عمران: ۱۸۵، سورۃ العنکبوت:۵۷)۔ جو یہاں آیا ہے، اسے بالآخر جانا ہے۔ ہمارے محترم اور نہایت ہی شفیق بزرگ جناب ڈاکٹر محمود احمد غاز ی رحمہ اللہ اسی الٰہی ضابطے کے تحت اپنی آخری منزل کی طرف چل دیے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔
ڈاکٹر غازی ؒ ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل انسان تھے۔ وہ بیک وقت ایک عالم دین، فقیہ، متکلم وخطیب، قانون دان، ماہر تعلیم، دانشور، مصلح اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ اگرچہ انہوں نے عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا، مگربہت اچھی سیاسی بصیرت رکھتے تھے۔ ان سے میر ا پہلا تعارف جولائی ۱۹۹۰ء میں ایک سیمینار کے دوران ہوا جس میں انہوں نے ’’ فرقہ بند ی اور معاشرے پر اس کے اثرات ‘‘ کے موضوع پر نہایت مدلل اور پرجوش خطاب فرمایا تھا۔ میں نے تقریر کے اختتام پر منتظمین سے درخواست کی کہ اس خطاب کا کیسٹ مجھے مہیا کیا جائے۔ انہوں نے کمال مہربانی سے وہ کیسٹ مجھے عطا کیا جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے متعدد بار اسے سنا اور اس کا عنوان اپنے طور پر بدل کر ’’ مسلمانوں میں فرقہ بندی کا افسانہ‘‘ رکھ لیا ا ور بہت سے لوگوں کو استفادے کے لیے دیتا رہا۔ بعد ازاں اسی موضوع پر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کی کتاب بھی مجھے مل گئی جو اپنی جگہ جامع ہے، مگر جو انداز، دلائل اور جوش و جذبہ ڈاکٹر غازی ؒ کے اس خطبے میں ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور ابھی تک برقرار ہے۔
دسمبر ۲۰۰۳ء میں ہم نے ایک سیمینار منعقد کیا اور اس میں ایک بار پھر ڈاکٹر محموداحمد غازیؒ کو مدعو کیا۔ اب کی بار ان کا موضوع: Religious Motivation and Geostrategic Compulsions of Pakistan تھا۔ عنوان انگریزی میں ہونے کے باوجودا ور خود انگریزی پرعبور رکھنے کے باوجود انہوں نے خطاب اردو میں کیا اور ایسا پر جوش خطاب کیا جس کی تازگی او رتحرک (Vibration ) ابھی تک برقرار ہے۔ پرویزی حکومت میں وزیر مذہبی امور ہونے کے باوجود انہوں نے جس بے باکی سے عالم اسلام کے اتحاد اور پاکستان کے مسلم دنیا کے حوالے سے کردار پر جذباتی انداز میں بات کی، اس نے ’’سب سے پہلے پاکستان‘‘ کے تصور کی دھجیاں اڑادیں اور نہ صرف پرویزی فکرکے تار و پود بکھیر دیے بلکہ مجھ سمیت بہت سو ں کو رُلا دیا۔ ان کے خطاب کا انداز بھی ہمیشہ منفرد ہوتا تھا۔ میں نے کبھی انہیں طویل تمہیدیں باندھتے نہیں سنا۔ حمد و ثنا کے فوراً بعدہی موضوع پر جوشیلے انداز سے بولنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کا ایک اورخطاب بعنوان ’’ اسلام میں تفریح کا تصور‘‘ تقریباً تین گھنٹوں پر مشتمل میرے پاس ہے۔ اس میں جیسے ہی تعارفی کلمات کے بعد انہیں مدعوکیا گیا، انہوں نے فوراً موضوع پر بولنا شروع کر دیا اور مسلسل بولتے رہے اور ایک ہی رفتار و آواز سے بولتے گئے۔ انتہائی سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسا ذو معنی جملہ بولتے کہ ہمہ تن گوش سامعین عین سنجیدگی کے عالم میں بے اختیار ہنس پڑتے۔
ڈاکٹر غازی ؒ کی ایک اور انفرادیت یہ تھی کہ وہ علما کے درمیان جدید دانشور لگتے تھے اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے مابین علما کے ترجمان و حمایتی محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والوں کو مطمئن کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ کسی بھی موضوع پر انہیں اظہار خیال کی دعوت دی جائے، لگتا تھا جیسے اسی کے متخصص (Specialist) ہیں۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ خاص طور پر مسلمانوں کے عروج وزوال کے اسباب سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان کی ایک تقریر اس موضوع پر میرے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے بڑے خوب صورت انداز میں اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنی تابناک تاریخ سے روشنی حاصل کر کے اپنے حال کو سنواریں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کریں۔ ان کی مسلسل کوشش تھی کہ مسلمانوں کو زوال کے اسباب سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان کا سد باب کیا جا سکے۔ اندلس (Spain) کی تاریخ کا خاص طور پر حوالہ دیتے تھے جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک شاندار طریقے سے حکومت کی اورعظیم الشان تہذیب وتمدن کی بنیادیں رکھیں۔پھر وہاں سے ان کا صفایا کردیا گیا۔غازی ؒ صاحب کے نزدیک حکمرانوں کو سب سے زیادہ تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔وہ کہتے ہیں کہ تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے،فرد اگر اپنا حافظہ بھول جائے تواس کا مقام پاگل خانہ ہوتا ہے،اگرقوم اپنا حافظہ کھو بیٹھے تو اس کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ قیادت پر فائز لوگوں کوتاریخ کا گہرا شعور ہونا چاہیے تاکہ قوم کی رہنمائی کا حق ادا کر سکیں۔ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص ۲۵)
ڈاکٹر صاحب قلم کے بھی شہسوارتھے اور متعددتحقیقی کتب کے مؤلف ومصنف تھے۔آپ نے سو سے زیادہ علمی وتحقیقی مقالے مختلف کانفرنسوں میں پیش فرمائے جن میں سے اکثر ملکی وبین الاقوامی جرائد میں طبع ہوچکے ہیں۔ وقیع علمی وتحقیقی کتب کے علاوہ ان کی بعض کتب تو ان کے خطابات سے ہی مرتب کی گئی ہیں۔ان میں سرفہرست محاضرات قرآنی،محاضرات حدیث اور محاضرات فقہ ہیں۔یہ خطابات مستورات کے اجتماعات میں مختصر نوٹس کی مدد سے دیے گئے تھے مگر ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غازی صاحبؒ کو علم سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر فقہ اسلامی کے ماہر تھے لیکن ان کی بعض دوسری تحریریں ان کے فکر کی بلندیوں اور وسعتوں کی گواہی دیتی ہیں۔میرے سامنے اس وقت ان کی ایک ایسی ہی تالیف ہے جس سے ان کے فکرکی ہمہ گیری کا پتہ چلتا ہے۔اس کاعنوان ہے: ’’محکمات عالم قرآنی، علامہ اقبال کی نظر میں، قرآنی دنیا کی امتیازی خصوصیات اور اس کی بنیادیں (جاوید نامہ کی روشنی میں)‘‘۔ یہ کتاب ڈاکٹر صاحب نے اپنی صاحبزادیوں کو املا کروائی تھی اوریہ معلوم ہے کہ املا کرانا اورالگ سے بیٹھ کرغوروخوض کر کے کسی موضوع پر لکھنے میں زمین وآسمان کا فرق ہوتا ہے۔ان کی یہ مختصر مگر جامع تالیف ان کی وسعت مطالعہ کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے فکروفلسفے سے کماحقہ آگاہی کی بھی آئینہ دار ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرغازیؒ صاحب کو بے پناہ ذہانت وفطانت سے نوازا تھا۔ میں نے جب بھی ان سے کوئی استفسار کیا یا کسی موضوع پر گفتگو کی، وہ فوراًاس کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ کوئی تین چار سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اسلامی یونیورسٹی ،فیصل مسجد میں اپنے دفتر میں تشریف فرما تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا ۔اثنائے گفتگو میں مغرب کا عالم اسلام کے ساتھ رویہ زیر بحث آیا تو فوراً مجھے اپنا ایک مضمون دراز سے نکال کر دیا جو’’تعمیر افکار‘‘ کی اشاعت بابت ماہ اکتوبر۲۰۰۷ء میں بھی چھپ چکا ہے۔ مضمون کا عنوان ہے’’اسلام ا ورمغرب۔ موجودہ صورت حال، امکانات، تجاویز‘‘۔ یہ بھی آپ کی فی البدیہ تقریر تھی جس کوصفحۂ قرطاس پر منتقل کر کے آپ کی نظر ثانی کے بعد شائع کیا گیا تھا۔ یہ مضمون مغربی دنیا کے حوالے سے آپ کی فکر کا نچوڑ ہے ۔اس کے ذریعے آپ نے بڑے جامع اندازسے مغرب کے مسلمانوں کے ساتھ رویے کا تجزیہ کیا ہے اور مسلمانوں کو مغربی طاقتوں کے عزائم سے خبردارکیا ہے۔ مغرب اوراسلام کی موجودہ کشمکش کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’امت مسلمہ کے عالم گیر کردار میں یہ بات بنیادی طور پر شامل ہے کہ ان کا ایک طویل عرصے تک یہودیوں اور عیسائیوں سے واسطہ رہے گا، مقابلے کی نوعیت پیش آتی رہے گی،تصادم ہوتا رہے گا،اوراس تصادم کے لیے مسلمانوں کویہ دو سورتیں (سورۃ البقرۃ، سورۃ آل عمران) تیار کر رہی ہیں‘‘۔ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص ۲۰)
موجودہ مغرب جس کا سرغنہ امریکہ ہے اورکبھی اس کا کرتا دھرتا برطانیہ تھا، ہر ایک کی رگ جاں پنجۂ یہود میں ہے۔ اس کے ڈانڈے بھی یہود ونصاریٰ کے آغاز اسلام کے طرزعمل سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر غازی ؒ کے الفاظ میں : ’’جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، اس سے مسلمانوں کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے شروع ہوگیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو نامۂ مبارک بھیجا۔ ہرقل مشرقی سلطنت روم کا فرماں روا تھا‘‘۔ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص ۲۰) گویا اس مخالفت کا اصل سبب دعوت اسلام بنی اورجب خلافت راشدہ کی صورت میں اسلام کا عادلانہ نظام اپنی بہاریں دکھانے لگا تو اس مخالفت میں اضافہ ہوگیا، کیونکہ قیصر کی خدائی خطر ے میں پڑگئی تھی۔اب کبریائی وخدائی صرف اللہ کا حق تھا۔ سارے انسان اللہ کی نیابت(خلافت)کے تو حقدارہو سکتے ہیں، لیکن خدائی منصب کسی کونہیں مل سکتا۔ اس کی عملی شکل خلافت راشدہ کے زمانے میں سامنے آئی توبندوں پر خدائی کا دعویٰ رکھنے والے خم ٹھونک کر میدان میں آگئے۔ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ میدان جنگ میں کیا۔غازیؒ صاحب لکھتے ہیں:
’’اس کے (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے) بعداصل تصادم اورمقابلہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا۔ صلیبی جنگوں کے بعد ایک طویل عرصے تک اسپین میں یہ مقابلہ جاری رہا، جنوبی یورپ کے ذریعے یہ سابقہ پیش آتا رہا۔ پھر استعمار اور ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد گزشتہ سوسال سے جوکچھ ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے‘‘۔ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص۲۰)
ڈاکٹر صاحب مرحوم کو شدیداحساس تھا کہ مغربی دنیا اوراقوام متحدہ جیسے نام نہاد عالمی ادارے مسلمان ملکوں کو بالعموم اورپاکستان کو بالخصوص اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:
’’جب گورے کی ہدایت آتی ہے کہ قیام امن کے لیے فلاں جگہ فوج بھیجواورمسلمانوں کی بندوقوں کے ذریعے مسلمانوں کو زیرکرکے ہمارے مفادات کے لیے راہ ہموار کرو ،تو تیمور میں بھی فوج چلی جاتی ہے،صومالیہ میں بھی چلی جاتی ہے اورایری ٹیریا میں بھی چلی جاتی ہے۔دنیائے اسلام کے سپاہیوں کے ذریعے ،دنیائے اسلام کی بندوقوں کے ذریعے،دنیائے اسلام کے مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جائیں،اور ان کو کاٹ کاٹ کرعیسائی اورمسیحی ریاستیں قائم کی جائیں۔‘‘ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص ۲۴)
انگریزوں کے گن گانے والوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہ ان کے ممدوح کتنے مہذب اور انسان دوست تھے، لکھتے ہیں:
’’انیسویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں میں پنجاب میں سوفیصد تعلیم تھی اور بحیثیت مجموعی ۸۴فیصد تھی اورجب انگریز ۱۹۴۷ء میں ہندوستان سے گیا تو پنجا ب میں مسلمانوں میں تعلیم کا تناسب ۴فیصد تھا۔ انگریز سوکو چار پر لے آئے اورپوری قوم کو جاہل چھوڑکرچلے گئے۔یہ ہے اس دعوے کی حقیقت جو کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک کا ایک سویلائزنگ رول تھا۔آج بھی ہمارے ہاں بہت سے سادہ لوح اور مشرق بے زار لوگ کہتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں سویلائز کردیا۔ یہ سویلائز کیاکہ سو فیصد تعلیم کوسو فیصد جہالت میں بدل دیا‘‘۔ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص ۲۶)
ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اپنا ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے جس سے مغربیوں کے سازشی کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
’’اکتوبر ۱۹۷۴ء میں ایک پروفیسر صاحب امریکہ سے تشریف لائے۔ وہ ایک مشہور امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ...وہ پروفیسر صاحب بہت سے لوگوں سے ملے،مجھ سے بھی ملے۔ مجھ سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں الگ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ میں ان سے ملنے چلا گیا۔ دوران ملاقات انہوں نے کہا، امریکہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تم جس یونیورسٹی میں چاہو، میں تمہیں اسکالرشپ دے سکتا ہوں۔.... میں نے کہا، مجھے ہارورڈ میں داخلہ دلوا دیں۔ انہوں نے کہاٹھیک ہے۔ ....تم ایک سال کے لیے امریکہ آؤ، ہارورڈ یونیورسٹی میں کورس ورک کرو۔ ....پھرواپس پاکستان آجاؤ۔ انہوں نے جو نقد وظیفہ بتایا، وہ اتنا تھا جتنا اس وقت حکومت پاکستان کے سیکرٹری کو بھی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ ...انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں رہ کر یہ معلومات جمع کرو کہ پاکستان میں دینی مدارس کیا کام کرتے ہیں، کتنے دینی مدارس ہیں، کون کون علماے کرام ان کو چلا رہے ہیں، وہ کیا کیا پڑھاتے ہیں، کیا ذہن بناتے ہیں اورجو لوگ ان سے تیار ہوتے ہیں، وہ بعد میں کیا کام کرتے ہیں، ان کا رویہ مغرب کے بارے میں کیسا ہوتا ہے؟ یہ ساری معلومات جمع کر کے آؤ، پھر میرے ساتھ بیٹھ کر اس کو مرتب کرو، اس کی بنیادپر تمہیں ہارورڈ یونیورسٹی پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دے گی‘‘۔ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص ۳۳)
غازی صاحب ؒ نے جس خوبصورتی سے مغرب کی مسلمانوں کوگمراہ کرنے کی تدابیر کا ذکرکیا ہے، وہ انھی کے ذہن رساسے ہی ممکن تھا۔اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ آمین۔
غازیؒ صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ وہ کھوکھلے نعروں سے اسلام کوبدنام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنے دورۂ ازبکستان کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
’’۱۹۹۰ء میں مجھے ازبکستان جانے کا موقع ملا۔ ...میں نے صدر ازبکستان سے کہاکہ ...آپ ازبک نوجوانوں کو ہمارے تعلیمی اداروں میں آنے کی اجازت دیں۔ صدر صاحب مسکرائے اورانہوں نے کسی سے اپنی زبان میں کچھ کہا اوراس نے ایک موٹی سی فائل لاکر صدر کے سامنے میز پر رکھ دی۔ صدرصاحب نے وہ فائل میری طرف لڑھکا دی۔ میں نے فائل کوکھولا تو اس میں اخبارات کے تراشے تھے اورہمارے پاکستان کے بہت سے مذہبی، دینی سیاسی قائدین کے بیانات تھے کہ ہم فلاں جگہ جھنڈا لہرا دیں گے اور سمرقند وبخارا کو آزاد کرا دیں گے ... جب میں اس فائل کی ورق گردانی کر چکا تو صدر ازبکستان کہنے لگے کہ تم یہ سب کرنے کے لیے طلبہ کو لے جانا چاہتے ہو؟ سچی بات یہ ہے کہ ... میرے پاس سوال کاجواب نہیں تھا‘‘۔ (تعمیر افکار، اکتوبر ۲۰۰۷ء ص ۳۴)
متذکرہ بالا اقتباسات سے عیاں ہے کہ غازی ؒ صاحب محدود معنی میں معلم و مدرس ہی نہیں تھے بلکہ عالمی حالات کا گہرا شعور بھی رکھتے تھے۔ طوالت سے بچتے ہو ئے مغرب کے چند جرائم کا ذکر کرنا ضروری ہے جن کو وہ عالم انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک سمجھتے تھے۔ مثلاً عالمگیریت (Globalization) کو وہ مسلمانوں کے وسائل پر قبضے اوران کے تشخص کو مٹانے کا ایک منصوبہ خیال کرتے تھے۔ مزید برآں وہ عالمگیریت کو انسانوں کے درمیان تفریق وتقسیم کا آلۂ کار گردانتے تھے۔ ان کی یہ پختہ رائے تھی کہ اہل مغرب کو اسلام کے حوالے سے کوئی غلط فہمی یا مغالطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ اسلام ومسلمانوں کی مخالفت کر کے وہ دنیا کی توجہ اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ و ہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ مغرب کے متعصبانہ رویے کے باوجود اسلام وہاں تیزی سے پھیل رہا ہے۔خاص طور پر طبقۂ خواتین اسلام کی طرف زیادہ رجوع کررہاہے۔
غازی ؒ صاحب کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے ۔آپ اپنی تعلیمی وتدریسی مصروفیات کے باوجود جس طرح تصنیف وتالیف کاکام بھی جاری رکھتے تھے، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ان ہمہ جہتی مشاغل کے باوجود طبیعت میں ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی۔دگر گوں حالات میں بھی پرامید (Optimistic) ہوتے تھے۔عالم اسلام کے حوالے سے کسی اندیشے میں مبتلا ہونے کی بجائے وہ ہمیشہ روشن مستقبل کی بات کرتے تھے۔
آپ سماجی ومعاشرتی تعلقات کا کتنا خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کی دل جوئی کے لیے اس کی سہیلی کی مہندی کی رسم میں ایک دفعہ شرکت کے لیے چلے گئے۔ یہ اور با ت ہے کہ وہاں پر جو ہندوانہ خرافات ورسومات دیکھیں تو ان پر بعد میں اپنی تقریر کے دوران تأسف کا اظہار بھی کیا اور کھل کر اس ہندوانہ ثقافت کی مخالفت کی اور بر ملا اعتراف بھی کیا کہ اس سے پہلے وہ اس قسم کی رسوم کو محض سماجی Gatherings سمجھتے تھے، لیکن متذکرہ محفل میں انہوں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں پیلے کپڑے پہنے، ہاتھوں میں گیندے کے پھول اٹھائے ہوئے اور عجیب وغریب انداز سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے محفل میں نمودارہوئے تووہ سخت پریشان ہوئے اور آئندہ کے لیے ایسی محافل میں شرکت نہ کرنے کا عزم کیا۔ ان کی مخالفت اور تنقید کا انداز بھی بہت پیارا ہوتا تھا۔ مثلاً انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کے دہرے معیار پرتبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ Dignity of man کی باتیں کرنے والوں کواسلام کے قانون قصاص پر بڑا اعتراض ہے کہ اس میں ایک جان ضائع ہو جاتی ہے۔ خود کسی سے انتقام لینا ہو تو بستیوں کی بستیاں تاراج کر لیں گے، لیکن قصاص میں ایک انگلی کے کٹنے پر یہ شور برپا کر دیتے ہیں۔ (روایت بالمعنی)
ڈاکٹر صاحب ؒ علم وعمل کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پایے کے منتظم بھی تھے۔ آپ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیا۔ یوں تو دعوۃ اکیڈمی،شریعہ اکیڈمی اوردیگر اداروں کے انتظام وانصرام باحسن طریق انجام دیے، مگر اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے آ پ نے جس نظم و نسق کا طلبہ واساتذہ کو پابند بنایا اور ایک مثالی تعلیمی ماحول قائم کیا، وہ قابل ستائش ہی نہیں قابل تقلید بھی تھا۔ عام طور پرڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کو صر ف ایک دینی سکالر اور ماہر تعلیم سمجھا جاتا ہے لیکن فی لواقع وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔وہ ایک مجتہد وفقہی ہونے کے علاوہ ایک مصلح کی سی شان کے حا مل بھی تھے۔ان کی بہت ہی پختہ رائے تھی کہ اسلام کے عادلانہ نظام کے اندر انسانیت کے تمام دکھوں کا مداوا موجود ہے اور آج اگر اس نظام عدل وقسط کودنیامیں قائم کر کے دکھا دیا جائے تو دنیا اسلام کی طرف لپک پڑے گی اور باطل نظاموں کے مظالم میں گھری ہو ئی انسانیت سکھ کا سانس لے سکے گی۔ وہ لکھتے ہیں:
’’عالم قرآنی یا قرآنی دنیا سے مراد انسانی زندگی کا وہ ڈھنگ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم وہدایات پر استوار ہو۔ گذشتہ تین صدیوں سے اسلامی ادبیات اور اسلامی فلسفہ سیاست وقانون کا سب سے اہم موضوع یہی رہا ہے کہ اس مثالی دنیا کو از سر نو دریافت کیا جائے جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، جو مشرق و مغرب کے اہل ایمان کے لیے ایک ایسے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے حصول کی خاطر نہ معلوم کتنی نسلیں قربانیاں دیتی چلی آرہی ہیں۔ نہ معلوم کتنی سعید روحیں اس ہدف کے حصول میں جانوں کا نذرانہ پیش کر چکی ہیں۔ نہ معلوم کتنے اہل علم و دانش کے شب و روز اس عالم منتظر کی تفصیلات پر غور و خوض کرنے میں صرف ہوئے ہیں۔ یہ عالم قرآنی دنیائے اسلام کی وہ منزل و مقصود ہے جس تک پہنچنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں نے جان و مال کی بازیاں لگائی ہیں۔ مسلم سیاسی مفکرین نے حکومت الہیہ، خلافت ربانی، اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے عنوانات کے تحت اسی جہان مطلوب کے چہرے سے نقاب اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ فقہائے اسلام نے نفاذ شریعت اور فقہ اسلامی کی تدوین نو کے موضوعات پر جو کچھ لکھا ہے وہ اسی ہدف کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے۔ احیائے اسلام اور ملت اسلامی کی نشأۃ ثانیہ کے لیے گزشتہ چند صدیوں میں جو کاوشیں ہوئی ہیں ان کی منزل مقصود بھی ایک ایسی دنیا کی تشکیل تھی جہاں قرآن مجید اور اسوہ رسول ؐ کو سامنے رکھ کر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اسلامی ڈھنگ اپنائے جاسکیں‘‘۔ (محکمات عالم قرآنی صفحہ۴، ۵)
ڈاکٹرصاحبؒ نے علامہ اقبال کے حوالے سے عالم قرآنی کے چار محکمات کا ذکر کیاہے یعنی ’’خلافت آدم، حکومت الٰہی، زمین ملک خدا ہے اور حکمت خیرکثیر ہے‘‘۔ (محکمات عالم قرآنی صفحہ۲۱) اسلام کے عادلانہ نظام، جس کو وہ عالم قرآنی کہتے ہیں، کے قیام کاخواب کبھی شرمندۂ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک علم الادیان اور علم الابدان کی دوئی کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اس ضمن میں ان کا موقف یہ تھا کہ دینی ومذہبی علوم، علم وحکمت کی اساس ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ علم وحکمت کے دائرے میں علم اسماء وعلم تجربی (Modern Scientific Knowlege) بھی شامل ہیں۔ علوم وفنون کی یہ وحدت اسلام کے تصور علم کی بنیادہے۔ تعلیم میں دوئی سے فکرو نظر میں دوئی پیداہوتی ہے اور فکرو نظر میں دوئی سے اس وحدت فکروعمل پر زد پڑتی ہے جو عقیدۂ توحید کے لازمی نتیجے کے طور پر امت مسلمہ میں قائم رہنی چاہیے۔
ڈاکٹرغازیؒ کی فکری پختگی کامظہران کی مغرب کے بارے میں منفردرائے ہے۔ وہ مغربی تہذیب کو Secular کی بجائے مسیحی کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
’’ہمارے ہاں بہت سے حضرات سادہ لوحی سے مغرب کا مطالعہ کرتے ہیں اور مغرب کے ظاہری دعووں سے متأثر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے مذہب کوگھر سے نکال دیا ہے اور اب مغرب ہر مذہبی تعصب سے آزاد ہے۔ وہ حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ مغرب نے مذہب کوایک خاص علاقے سے نکالا ہے، گھر سے نہیں نکالا۔ مغرب کی ہر چیزعیسائی تہذیب وتمدن، عیسائی روایات اور عیسائی تعصبات پر مبنی ہے‘‘۔ (تعمیرافکار، اکتوبر ۲۰۰ء، ص ۲۱)
ڈاکٹر محموداحمدغازی رحمہ اللہ کی زندگی کے یہ وہ پہلوہیں جن کا کسی درجے میں راقم الحروف کوعلم تھا۔ آئندہ کوئی صاحب عزم وہمت ان کی زندگی پر تحقیق کرکے ان کی شخصیت کے مزیدپہلوؤں کو اجاگرکرسکتا ہے۔ ایسی نابغۂ روزگار شخصیات کے بارے میں آگاہی آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا کام دے گی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی دینی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کوان کا سا جذبہ اوراخلاص عطا فرمائے۔ جس لگن ومحنت سے انہوں نے دین وملت کی خدمت کا فریضہ بحسن وخوبی انجام دیا، اللہ ہمیں اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اللھم اغفرلہ وارحمہ وحاسبہ حسابا یسیرا۔ آمین یا رب العٰلمین۔
اک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا
محمد رشید
۲۶ ستمبر ۲۰۱۰ء کو میرے موبائل پر میسج ابھرا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی وفات پاگئے ہیں۔ میسج کیا ابھرا کہ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دُکھ اور محرومی کا ایک گہرا احساس روح میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ مملکت پاکستان جس پر آج کل چہار اطراف سے آفات حملہ آور ہیں،ان حالات میں وہ کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوگئی ہے، یہ سوچ کر ہی دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔
جن علمی و دینی شخصیات کی علمی کاوشوں سے ہم استفادہ کرتے رہے ہیں، ان میں سے سال ۲۰۱۰ء میں یہ دوسری علمی و دینی شخصیت ہے جن کی وفات ذاتی نقصان کی طرح دکھی و پریشان کرگئی۔اگرچہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم و مغفور کی وفات پر بھی دل پر ایک چوٹ پڑی، روح کی گہرائیوں میں چھناکے سے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی کی وفات نے تو محض دکھی ہی نہیں کیا، دل سخت بے چینی وکرب سے بھی دوچار ہوگیا۔ یہ بات واقعتا ہمارے لیے بھی خاصی حیران کن تھی کہ جس شخص سے ہم زندگی میں ایک بار بھی نہیں ملے ، اس کی وفات پر دُکھ کا ایسا احساس تھا کہ آنسو اندر ہی اندر گلے سے اتر کر دل کے پار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔
ڈاکٹر غازی صاحب سے ہماری پہلی غائبانہ ملاقات ان کی کتاب ’’محاضراتِ قرآن‘‘ میں ہوئی۔ ان کی یہ کتاب پڑھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ایک مخلص، ذہین، علوم پر گہری دسترس رکھنے والے، ابلاغ کی قوت سے مالا مال، بات کو عام فہم اور سلیس انداز سے سامع تک پہنچانے والے، علم و تحقیق سے شغف رکھنے والے ، جدید پڑھے لکھے انسان کے سامنے دین کو پیش کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ایک سادہ اور حلیم طبیعت کے مالک انسان ہیں۔
ڈاکٹر غازی صاحب سے ہماری دوسری غائبانہ ملاقات قدرے مختلف تاثرات کی حامل ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ ہمیں ’’علم حدیث‘‘ پر جدید محققین کے کام اور آرا کا مطالعہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے اور کسی قدر خوف و امید کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ڈاکٹر غازی صاحب کی کتاب ’’محاضرات حدیث‘‘ کا مطالعہ شروع کیا۔ ہمیں ڈریہ تھا کہ ڈاکٹر غازی صاحب کے بارے میں ہمارا جو تاثر بن چکا تھا، وہ کہیں اس کتاب کے مطالعہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ غازی صاحب جیسا فطین اور عبقری شخص حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہیں راہ اعتدال سے ہٹ نہ جائے جیسا کہ آج کل کے ذہین لوگوں کا المیہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اچھے بھلے دین پر چلتے چلتے ’’منکرین حدیث‘‘ کے ’’پرویزی حیلوں‘‘ میں ایسے پھنستے ہیں کہ ان کے دماغ کو لاکھ اس گورکھ دھندے اور دلدل سے نکالنے کی کوشش کرو، ’’ذہانت اور فطانت‘‘ کا فتنہ انہیں اس جال سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔خیر! ہم جوں جوں اس کتاب کے مطالعے میں آگے بڑھتے گئے، قدرے مختلف گہرے تاثرات میں پھنستے چلے گئے۔ کتاب پڑھنے کے بعد ہم اس خوشگوار تاثر سے ہم کنار ہوئے کہ عصر ی مغربی علوم پر گہری نظر رکھنے والا، جدید دنیا میں رہنے والا، جدید دنیا کے پڑھے لکھے انسانوں سے میل جول رکھنے والا ایک ذہین اور فطین انسان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں بھی معذرت خواہی یا کجی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔
ہم پر ایک اور انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی چودہ سوسالہ تاریخ کی علمی و تحقیقی کاوشوں کو موثر اور سلیس انداز میں پیش کرنے کاایسا ملکہ رکھتے ہیں کہ جدید دور کا انسان متاثر اور مبہوت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ وہ خوبی ہے جو انہیں موجودہ دور کے قدیم و جدید علوم کے تمام علما سے بہت بلند، منفرداور نمایاں مقام عطا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹرغازی صاحب کو پڑھ کو ہمیں پہلی دفعہ ’’علمی اور عقلی‘‘ سطح پر اپنے اسلاف پر فخر محسوس ہوا، ورنہ عام طور پر مذہبی علوم کے علما اسلاف کے علمی ورثے کو جس ’’انداز‘‘ سے پیش کرتے ہیں، اس سے جدید تعلیم یافتہ انسان متاثر تو کیا ہو، اسے ایک قسم کا توحش اور اجنبیت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹرغازی صاحب کی اس دوسری کتاب کو پڑھ کر ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ ’’عقائداوربنیادی فکر‘‘ کے معاملہ میں مولویوں سے زیادہ پختگی، اعتدال اور توازن پر کاربند ہیں۔
ڈاکٹر غازی صاحب کی تحریریں پڑھ کر کچھ اورخوبیوں کا تاثر دل پر پڑا، لیکن خدشہ ہوا کہ اگر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو شاید یہ تاثر ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے شدید خواہش کے باوجود ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد مورخہ ۲۰۱۰ء/۹/۲۸ کو روزنامہ اسلام میں ڈاکٹر سید عزیز الرحمن نے ان الفاظ میں ان کی شخصیت کا نقشہ کھینچا: ’’ڈاکٹر صاحب حد درجہ متقی شخص تھے۔ برس ہا برس کا مشاہدہ ہے کہ سرکاری و دفتری ذمے داریوں میں سرکاری مراعات سے کبھی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا وجود عالم اسلام کے لیے بساغنیمت تھا۔ بین الاقوامی فورم پر اسلام اور پاکستان کی نمائندگی کا جو سلیقہ ڈاکٹر صاحب کو حاصل تھا، اس کی مثال کم ملے گی۔ پھر علم و فضل اور دینی حمیت و تصلب کے ساتھ ساتھ حسن تکلم و حکمت کی دولت سے آراستہ تھے۔‘‘
اسی طرح مورخہ ۳۰؍ ستمبر کے روزنامہ اسلام میں مولانا ازہر نے ان الفاظ میں ان کی شخصیت کا نقشہ کھینچا: ’’راقم السطور کو دوچار مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں بیٹھنے اور کسی حد تک استفادہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ غیر معمولی علمی مقام کے باوجود ان کے عجز و انکسار، سادگی، نرم مزاجی اور دھیمے پن نے احقر کو بہت متاثر کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سلاست، بلاغت، متانت اور فقاہت کا مرقع ہوتی تھی۔‘‘
یہ گواہیاں پڑھ کر جہاں ڈاکٹر غازی صاحب کے بارے دل جو گواہی دے رہا تھا، اس کی تصدیق ہوگئی، وہاں ان سے ملاقات سے محرومی کا احساس بھی سوا ہو گیا۔
روزنامہ اسلام میں پڑھ کر سخت حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر غازی صاحب کا خاندانی و تعلیمی پس منظر خالصتاً مولویانہ اور مذہبی ہے۔حیرت ہے، سخت حیرت پر حیرت ہے کہ ۲۰۱۰ء کے اس سخت زوال و تباہی کے دور میں بھی مدرسہ و خانقاہ کا پس منظر رکھنے والی ایک شخصیت علم و کردار کی ان بلندیوں پرپہنچ جاتی ہے کہ قدیم و جدید علوم کے بڑے سے بڑے ماہرین بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔اے کاش ! ہمارے مدرسہ و خانقاہ کے نظام میں ایسی کوئی اصلاح ہو جائے کہ وہ ڈاکٹر غازی صاحب جیسی ہستیاں پیدا کرنے لگ جائے تونوع انسانی میں ایک بہت بڑے تعمیری انقلاب اور مثبت تبدیلی کی بنیاد ڈالی جاسکتی ہے۔ ہمارے سیاسی و مذہبی ہردوراہنماؤں کویہ بات پلے باندھ لینا چاہیے کہ دینی حمیت و تصلب کے ساتھ ساتھ حسن تکلم و حکمت ،عجز و انکسار، سادگی، نرم مزاجی،سلاست، بلاغت اور متانت کردار کی وہ بنیادی خوبیاں ہیں جس کے بغیر رہنمائی اور قیادت ایک خواب اور سراب ہے اور جس کے بغیر تعمیری انقلاب اور مثبت تبدیلی کی خواہش کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔
دل کی گہرائیوں سے یہ ندانکل رہی ہے کہ اے کاش! اس امت میں بہت سے ’’ڈاکٹر محمود غازی‘‘ پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ ہمارے بے چین اور مضطردل کی یہ دعاہے۔ مضطر اور بے چین کی پکار بھلا کون سنتا ہے۔۔۔ صرف اللہ۔
آفتاب علم و عمل
مولانا ڈاکٹر صالح الدین حقانی
فنا ایک اٹل حقیقت اور عالمگیر صداقت ہے جس سے آج تک کوئی انکار نہیں کرسکااور موت سے کسی کو رستگاری نہیں۔ دوام اور بقا صرف خدائے برتر کے لیے ہے۔ دنیاایک ایساعالم ہے جس کی کسی بھی چیز کو دوام حاصل نہیں ہے۔ ہر چیز عدم کی طرف رواں دواں ہے۔ حرکت جمود کی طرف گامزن ہے اور زندگی موت کے بے رحم پہرے میں سفر کرتی ہے۔ ہر چیز بزبان حال یہ اعلان کرتی نظر آتی ہے کہ ہر شے کو کسی نہ کسی دن فنا ہونا ہے۔ کسی کو مہلت کم ملتی ہے تو کسی کو زیادہ۔ کامیاب وہ انسان ہے جو موت کو اپنے لیے خوشگوار مرحلہ بنالے کہ فنا بھی اس کو فنا نہ کرسکے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے، خواہ اپنے افکار کی صورت میں یا اپنے قلم کے ذریعے یا ایسی خدمات کے ذریعے جس سے پوری قوم مستفید ہو۔ اس بقا کی بہترین صورت ’’ علم ‘‘ ہے جس سے اہل علم کی ایسی جماعت تیار ہو جو استاد کو لازوال بنا دے۔ ایسی ہی لازوال ہستیوں میں استاذ محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ بھی تھے جو ۲۶ ستمبر۲۰۱۰ء کو بعد از نماز فجر دل کے دورے سے انتقال فرماگئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل یہ کیفیت ہے کہ منطوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق عین الیقین کے درجہ میں سامنے آ رہا ہے۔ (آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تنگ فرما دے گا۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ تنگی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ’’بقبض العلماء‘‘، وہ علمائے ربانیین کو اٹھا لے گا۔)
مئی سے ستمبر ۲۰۱۰ء کے دوران میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانچ بڑے بزرگ اور جید علماے کرام دارفانی سے داربقا کی طرف رخصت ہوگئے۔ ان میں سے خواجہ خان محمد صاحب (۵؍ مئی ۲۰۱۰ء)، راولاکوٹ (آزاد کشمیر) کے خان اشرف صاحب (۱۸؍اگست۲۰۱۰ء)، ان کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں پلندری (آزاد کشمیر) کے بزرگ مولانا محمد یوسف خان صاحب، پھر قاضی عبداللطیف صاحب آف کلاچی ، پھر وانا کی ایک بزرگ شخصیت حضرت مولانا نور محمد صاحب شامل ہیں۔ ان مذکورہ جبال العلم کے فراق سے بندہ کے دل کے زخم ابھی مندمل نہیں ہو ئے تھے کہ ا یک اور جگر خراش اور جانکاہ اطلاع ملی کہ استاذ محترم ڈاکٹر محمود احمدغازی نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا ہے۔
یہ ۲۰۰۳ء کی بات ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحبؒ کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے بحیثیت مہمان خصوصی ایم فل علوم اسلامیہ کے اسکالرز سے خطاب کرنے کے لیے زحمت دی گئی تھی۔ آپ کے لیکچر کا عنوان تھا: ’’مشرقی اور مغربی علوم کا تقا بلی اور تنقیدی جائزہ‘‘۔آپ کے لیکچر سے پہلے استاذ محترم ڈاکٹر محمد ضیاء الحق نے فرمایا کہ کیا آپ ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں؟ بس ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے جن کا ہر بیان ایک تحقیقی مقالے سے کم نہیں ہوا کرتا۔ آپ توجہ اور دھیان سے ان کا لیکچر سنیں گے اور مجھے امید واثق ہے کہ ان کا یہ لیکچر آپ کے لیے تحقیقی مراحل میں تازیانہ اور مہمیز کا کام دے گا۔ دو گھنٹوں پر مشتمل ڈاکٹر صاحب کے لیکچر نے آپ کو ہزار گنا زیادہ ارفع ثابت کر دیا۔
اس ورکشاپ کے ایک مہینہ بعد یونیورسٹی نے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کانفرنس منعقد کی جس میں بطور مہمان خصوصی آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے اپنے استاذ محترم ڈاکٹر محمد حمیداللہ کی آرا وافکار اور خدمات کو جس انداز سے پیش کیا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ چائے کے وقفہ میں استاذ محترم ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ’’یہ حقانی صاحب ہیں، ایک ممتاز عالم دین مولانا محمد کامل شاہ صاحب کے فرزند ارجمند اور ان کے علمی ورثے کے امین ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم فل (علوم اسلامیہ) کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ ’’بسطۃ فی العلم والجسم‘‘ کے صحیح مصداق ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے‘‘۔ اس پر ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے: ’’ہمیں تو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور یہی ہمارا اصل سرمایہ اور امت کی راہنمائی کی اہلیت رکھنے والے چند گنے چنے افراد ہیں‘‘۔ پھر فرمایا: حقانی صاحب! کبھی یونیورسٹی تشریف لائیں تاکہ تفصیلی نشست کی جائے۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دل بے اختیار کہنے لگا:
کہاں میں اور کہاں نکہت گل
نسیم صبح، تیری مہربانی
ایک ہفتہ کے بعد میں یونیورسٹی حاضر ہوا۔ سلام کے بعد آپ فرمانے لگے، حقانی صاحب! بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہو ئی، کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا کہ ایک نشست کے لیے وقت چاہیے۔ فرمانے لگے: Most Welcome۔ کل تو میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان جارہاہوں، لہٰذا پرسوں مغرب کے بعد تشریف لے آئیں۔ حسب ارشاد میں پندرہ منٹ پہلے پہنچ گیا۔ آپ انتظار فرمارہے تھے۔ بڑے مشفقانہ انداز سے گلے ملے اور ایسا پیار دیا جیسے ایک مشفق باپ دیتا ہے۔ ہماری ون ٹوون پروقار مجلس شروع ہو ئی۔ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کی بابت جب میں نے ایک سوال کیا تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد مزید فرمایا:
’’ حقانی صاحب! سچی بات یہ ہے کہ دور جدید ایک پیچیدہ دور ہے۔ اس دور کے ارادے، تصورات اور اس دور کے معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس کے لیے بڑی خصوصی مہارتیں درکار ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مثلاً ’’بلاسود بینکاری‘‘ کا ایک بڑا چیلنج درپیش ہے، لیکن پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو شریعت کا بھی عمیق علم رکھتے ہوں اور جدید بینکاری کے تقاضوں کو مکمل طور پر سمجھتے ہوں، اس طرح کہ دنیا بھر کی سطح پر بینکاروں سے مقابلہ کرسکیں؟ تو کیا یہ ہم پر فرض کفایہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کے ایسے مایہ ناز اور اصحاب بصیرت ماہرین پیدا کریں جو دینی ماحول، دینی تربیت اور دینی ذوق ومزاج کے ساتھ ساتھ دور جدید کے معیار کی فنی مہارت رکھتے ہوں؟‘‘
استدلال کے طور پر آپ نے دو واقعات سنائے۔ فرمایا: حقانی صاحب! امام احمد بن حنبل ؒ جیسا متبع سنت اور فقیہ ان کے دور میں کوئی نہیں گزرا ۔ ان سے کسی نے مشورہ کیا کہ فلاں جگہ جہاد کا معاملہ درپیش ہے۔ مختلف علاقوں سے افواج، رضاکاروں اور مجاہدین کے دستے جارہے ہیں۔ ایک فوجی کمانڈر کی سربراہی میں ایک بڑا دستہ تیار ہو رہا ہے۔ وہ کمانڈر بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، بڑا نمازی اور شب زندہ دار ہے، لیکن سیاسی وعسکری معاملات میں خاص ماہر نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسرا شخص ہے جو زیادہ دیندار اور نیک تو نہیں ہے، لیکن اس کی عسکری مہارت بڑی مسلم ہے تو فرمائیے کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل ؒ نے فرمایا: جو شخص نیک ومتقی ہے، لیکن عسکری مہارت میں کم درجہ رکھتا ہے، اس کی نیکی وتقویٰ کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا اور اس کی عسکری عدم مہارت کا نقصان پوری قوم اور اسلامی فوج کو ہوگا۔ جو شخص زیادہ نیک نہیں ہے، اس کی نیکی کی کمی کا جو نقصان ہے، وہ تو صرف اس کی ذات کو ہوگا، لیکن اس کی عسکری ’’مہارت‘‘ کا فائدہ پوری مسلم امہ کو ہوگا‘‘۔
مزید فرمایا: بڑی خوشی ہوئی کہ آپ درس نظامی، حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سائنس گریجویٹ بھی ہیں، کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے اہل علم جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم بھی رکھتے ہوں، ان کی بات کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے اور جو دورجدید کے محاورے میں اپنی بات کو بیان نہیں کر پاتے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس صورت حال پر یہ کہنا کہ ’’ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو سمجھانے کی، جس کو سمجھنا ہو خود ہمارے پاس آئے اور ہمارا محاورہ اور اسلوب سیکھ کر آئے‘‘ مجھے اس بات سے ہرگز اتفاق نہیں۔ اسلام پر کسی فرد یا مخصوص طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ تمام نسلوں، زمانوں اور قوموں کے لیے ہے، اس لیے اس کے پھیلاؤ کی راہ میں جو بھی جس انداز سے رکاوٹ بنے گا، اسے اپنا انجام یوم آخرت کو پیش نظر رکھ کر سوچ لینا چاہیے۔
اپنے ایم فل کے مقالے کے سلسلے میں موضوع کی بابت رہنمائی چاہی تو بڑی قیمتی آرا سے مستفید فرمایا، خصوصاً اپنے استاذ محترم کے نام سے موسوم ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری (فیصل مسجد، اسلام آباد) سے استفادے کی ترغیب دی۔ آپ کے ساتھ اس تفصیلی نشست نے میرے لیے مہمیز کا کام دیا اور میں نے بجائے ایک سال کے صرف دس مہینے میں عربی زبان میں ۳۰۸ صفحات پر مشتمل اپنا ایم فل کا مقالہ بعنوان ’’الامام زفر وآراؤہ الفقہیۃ: دراسۃ و نقدا‘‘ پیش کرکے ایم فل کی ڈگری حاصل کرلی۔ استاذ محترم کے ساتھ یہ میری پہلی اور آخری نشست تھی۔ اس کے بعد سیمینارز اور کانفرنسوں میں ملاقات اور اسی طرح بذریعہ فون سلام دعا ہوتی رہتی تھی۔
امسال عیدالفطر کے موقع پر میں نے گزارش کی کہ حضرت! آپ نے ہماری خانقاہ کو رونق بخشنے کا کافی عرصے سے جووعدہ فرما رکھا ہے، کیا میں اس کا خیال ذہن سے نکال دو ں؟ آپ نے فرمایا کہ صالح الدین! اگر زندگی نے وفا کی اور داعئ اجل نے تھوڑی مزید مہلت دی تو میرا ایک پروگرام اکتوبر کے پہلے ہفتے میں الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں اپنے بھائی (مولانا زاہد الرشدی) کے ساتھ طے ہوا ہے۔ ان شاء اللہ سیمینار سے فراغت کے بعد یا اس سے پہلے آؤں گا، لیکن بفحوائے ’’تدبیر کند بندہ ، تقدیر زند خندہ‘‘ ۲۶ ؍ستمبر ۲۰۱۰ء کو بعد از نماز فجر جان، جان آفریں کے سپرد کر دی اور عمر بھر کا تھکا مسافر جو شاید ہی کبھی اطمینان کی نیند سویا ہو، منزل پر پہنچ کر میٹھی نیند سوگیا، لیکن ان کی یادیں، ان کی علمی خدمات اور ان کے شذرات قلم سے مستفیدین کا ایک نہ ختم ہو نے والا سلسلہ انھیں صدیوں زندہ رکھے گا۔
وقت ایک ایسی دولت ہے جو شاہ وگدا، امیر وغریب، چھوٹے اور بڑے، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں ملتی ہے۔ اس کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب جبکہ ایک مہذب انسان فرشتہ سیرت بن سکتا ہے۔ اس کی بدولت ایک جاہل، عالم اور ایک نادان، دانا بن سکتا ہے، اس لیے مشہور ہے کہ جو شخص وقت کی قدرکرتا ہے، وہ زمانے میں قیادت وسیادت سنبھال سکتا ہے۔ استاذ محترم کو وقت کی قدر دانی کا عظیم وصف ورثہ میں ملا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایسا نظام الاوقات بنایا ہوا تھا کہ جس میں وقت کا ایک ایک لمحہ تلاش علم، اسلام کی نشرواشاعت، دعوت وتبلیغ، تقریر وتحریراور عمیق ودقیق مسائل کے حل میں گزرتا تھا، یہاں تک کہ دوران سفر بھی تصنیف وتالیف کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔
ایں سعادت بزورِ بازو نیست
تا نہ بخشد خداے بخشندہ
استاذ محترم کی علمی اور دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع وعریض تھا۔ دورِ جدید کے فکری وتہذیبی مزاج اور نفسیات سے آپ پوری طرح آگاہ تھے اور بالخصوص آج کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کو فکر وفلسفہ، تہذیب ومعاشرت ، علم وتحقیق اور نظام وقانون کے دائروں میں جن مسائل کا سامنا ہے ، آپ انتہائی وسعت نظر، گہرائی اور بصیرت کے ساتھ ان کا تجزیہ کرسکتے تھے۔ اسی طرح آپ کی عملی خدمات کا دائرہ بھی مختلف شعبوں میں پھیلا ہوا تھا اور آپ نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، ادارۂ تحقیقات اسلامی اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کی اعلیٰ جامعات کو بھی اپنے علم وفضل سے سیراب کیا، جبکہ وفات کے وقت آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی حیثیت سے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ اس قدر اسفار ، کثرت مشاغل اور مختلف اداروں کی ذمہ داریوں کے باوجود آپ نے مختلف موضوعات پر بڑی مفید کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔
محاضرات کے عنوان سے آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور سیرت پر مفصل خطبات دیے۔ یہ خطبات مختصر نوٹس کی مدد سے زبانی دیے گئے تھے جن کو بعد میں محترمہ عذرا نسیم فاروقی نے صوتی مسجل (Tape recorder) سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا۔ ان خطبات کے انداز بیان میں اگرچہ بنیادی طور پر علما اورمحققین کو سامنے نہیں رکھا گیا، لیکن پھر بھی علما اور محققین کے ہاں ان محاضرات کو بے حد پذیرائی ملی ہے۔ بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ استاذ محترم قدیم وجدید دینی اور دنیوی علوم کے ایسے سنگم بن گئے تھے جس میں مختلف علوم وفنون کی حسین لہریں جمع تھیں ۔
حقیقت یہ ہے کہ ایسی باکمال وبے مثال، باوقار وبامراد شخصیت کے حالات زندگی کو چند صفحات میں بیان کرنا جوے شیر لانے کے مترادف ہے اور پھر مجھ جیسا طفل مکتب آپ کے اخلاق وآداب، کمالات وامتیازات کو کیسے بیان کر سکتا ہے جس کی نہ عقل کی اتنی پرواز کہ استاذ محترم کی بلندیوں کو چھوسکے، نہ قلب میں اتنی سکت کہ وہ آپ کی اداؤں کا ادراک کرسکے، نہ فکر میں اتنی بلندی کہ وہ آپ کے مزاج ومزاق کو پہچان سکے، نہ طبیعت میں وہ جولانی کہ وہ آپ کے مقام کو جانچ سکے اور نہ قلم میں اتنی روانی کہ وہ آپ کی اداؤں کو بیان کرسکے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ استاذ محترم کے پس ماندگان اور ان کے جانشینوں کو ان کے قدم پر چلائے اور ان کو اپنی شایان شان اعلیٰ مقام نصیب فرمائے ۔ آمین
شمع روشن بجھ گئی
مولانا سید متین احمد شاہ
۲۶ ستمبر ۲۰۱۰ء کی سہانی صبح تھی۔ مہر درخشاں، ملکۂ عالم کی رسمِ تاجپوشی کے لیے مشرقی افق سے کافی بلندی پہ آچکا تھا۔ فطرت کا حسین منظر، عنادل کا شور، صبح بنارس کی مانند باد نسیم کی اٹھکیلیاں۔ اس جمالِ دل فروز کے جلو میں میں اسلام آباد کی ایک شارع عام پر محوِ سفر تھا کہ ایک پیغام موصول ہوا: ’’ڈاکٹر محمود احمد غازی کا انتقال ہوگیا۔‘‘ مولانا عمار خان ناصر صاحب کو فون کیا تو خبر کی تصدیق ہوگئی۔ دل غمگین ہوا، نینوں سے اشک چھلکے اور صبر وشکیب کا خرمن پل دو پل میں خاکستر ہوگیا۔ اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ عروس فطرت آج کس کے استقبال میں اپنی سج دھج دکھا رہی ہے اور ۲۴؍جنوری ۲۰۱۰ء کو کردار کے ’’غازی‘‘ سے ہونے والی پہلی اور آخری ملاقات کی جھلکیاں سامنے آنے لگیں اور میں خود کلامی کے خاموش پربت کے دامن میں فروکش ہوگیا۔
کیا ڈاکٹر غازی کا انتقال ہوگیا؟
سورۂ رحمن پکار کر کہنے لگی: کُلُّ مَنْ عَلَیْھا فَانٍ۔
خیال آیا: کیا آج اورنگ فکر کا سلیمان اپنے دربار کو سونا کر گیا؟
سورۂ انبیاء نے جواب دیا: کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَۃُ الْمَوْتِ۔
تخیل نے پوچھا: کیا آج ہم ایک ایسی محرومی سے دوچار ہو چکے ہیں جس کی تلافی اب نہ ہوسکے گی؟
قطری بن فجأۃ نے آکر تسلی دی:
فصبراً فی مجال الموت صبراً
فما نیل الخلود بمستطاع
اک ہوک سی اٹھی: ہائے! کیا واقعی؟
روح اقبالؒ نے خطاب کیا:
موت ہے ہنگامہ آرام قلزمِ خاموش میں
ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں
اتنے جوابات مل جانے کے بعد بھی یقین کا سرمایہ کہاں سے لاتا؟
مری بے تاب نظریں ڈھونڈتی پھرتی ہیں گلشن میں
صبا تو نے کہاں لے جا کے خاک آشیاں کھو دی
ڈاکٹر محمود احمد غازی (اللہ ان کو جنت الفردوس کی ابدی بہاروں کا مکین بنائے) کے نام سے شناسائی مجھے بچوں کے ایک جریدے ماہنامہ ’’مجاہد‘‘ کے ذریعہ گیارہ برس کی عمر میں حاصل ہوئی جبکہ وہ دعوۃ اکیڈمی اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ میٹرک کے امتحان کے بعد علامہ عبداللہ یوسف علی کا انگریزی ترجمہ قرآن لیا۔ اس پر ڈاکٹر غازی کے لکھے گئے جامع دیباچہ سے ان کے علمی مقام کا نقش اوّلین دل پہ مرتسم ہوگیا۔ مختلف جرائد کی وساطت سے ان کے البیلے مضامین کی ایک ایک سطر علم وآگہی میں اضافہ کا موجب تو بنتی ہی تھی مگر باضابطہ طور پر ان کے فکری و علمی آفاق کی وسعت و عظمت کا ادراک ان کے عظیم سلسلہ محاضرات کے ذریعہ ہوا۔ علوم، موضوعات اور مضامین کے اس تنوع کی مثال یکجا طور پر شاید عربی زبان میں بھی مشکل سے ملے۔ اپنی خوابگاہ کی الماری میں میں نے ان خطبات کو قرینے سے رکھا ہے اور ڈاکٹر غازیؒ کی وفات کے بعد آج تک کتنی بار ایسا ہوا کہ ان پر نظر پڑی تو دل پہ رقت طاری ہوگئی، آنکھوں سے آنسو چلنے لگے اوربے اختیار ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے اٹھ گئے۔
۲۴؍جنوری ۲۰۱۰ء کو ایک ساتھی نے ڈاکٹر غازیؒ سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا کیونکہ اپنے ایم فل کے مقالے کے لیے ’’نظم قرآن‘‘ کے تصور پر ڈاکٹر غازیؒ کے علم سے استفادہ بھی مقصود تھا۔ یہ ملاقات ان سے زندگی کی پہلی اور آخری ملاقات تھی اور اس نے ان کی تواضع، محبت اور وقار ومتانت کا ایک گہرا تاثر دل پر چھوڑا۔ ڈاکٹر محمد میاں صدیقی صاحب بھی ڈاکٹر غازیؒ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ملاحظہ کیا کہ ان کی عمر کے احترام کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب نے بہت کم گفتگو فرمائی اور صرف اسی سوال کا جواب خود ارشاد فرمایا جو انھی سے تعلق رکھتا تھا۔ سلسلہ گفتگو میں امام شاطبی ؒ کی کتاب ’’الموافقات‘‘ کا کسی حوالہ سے میں نے ذکر کیا اور اپنی لاعلمی سے اس کو ’بکسر الفاء‘ ادا کیا۔ انہوں نے فوراً اصلاح فرمائی کہ یہ لفظ ’بفتح الفاء‘ ہے اور یوں مجھے ایک لفظ میں ڈاکٹر غازیؒ کے تلمذ کا اعزاز مل گیا اور یہی کیا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سیکھایا میں اس کا غلام ہوں چاہے مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔
سلسلہ مراسلت قائم کرنے کے لیے میں نے ای میل مانگا تو انہوں نے لکھوایا:
mahmoodghazi23@yahoo.com
فرمایا کہ یہاں ۲۳ کا عدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوت کی مدت کی طرف اشارہ ہے۔ اتنے معمولی امور میں بھی اس بات کا خیال ان کی ذاتِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ومحبت کی روشن دلیل ہے۔ اس مختصر ملاقات میں بھی ڈاکٹر غازیؒ کے خوانِ علم سے مجھ جیسا کم سواد طالب بہت کچھ لے کر اٹھا۔
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد کے اولڈ کیمپس (فیصل مسجد) میں ڈاکٹر غازیؒ پر ایک تعزیتی ریفرنس میں ڈاکٹر شیر محمد زمان صاحب نے فرمایا کہ ہماری رفاقت طویل عرصہ پر محیط ہے اور اس کی روشنی میں بلاخوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ڈاکٹر غازی جن مناصب پر رہے اور ان میں چھوٹے چھوٹے امور میں بھی انہوں نے جس دیانت،تقویٰ اور ورع کا مظاہرہ کیا، اس کی اب کوئی دوسری مثال میں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔
ڈاکٹر غازیؒ کے علمی ذوق اور ولولہ کے حوالہ سے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب نے فرمایا کہ ایک بار غازی صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے امام شافعیؒ کی کتاب ’’الأم‘‘ کا سات مرتبہ از اوّل تا آخر مطالعہ کیا ہے۔ باریک ٹائپ سے لکھے گئے سات جلدوں کے اتنے بڑے علمی موسوعہ کو سات مرتبہ بالاستیعاب پڑھنے کی نظیر اس دور میں شاید مشکل ہی سے ملے گی جہاں اب تن آسانی، تضییع اوقات اور سطحیت ایک عمومی مزاج بن چکا ہے۔جامعۃ الرشید کی ایک مجلس میں ڈاکٹر صاحب نے علماے کرام سے فرمایا کہ میں اس کو عالم نہیں مانتا جس نے ہدایہ کم ازکم پانچ بار بالا ستیعاب نہ پڑھی ہو۔ میں تین بار پڑھ چکا ہوں، چوتھی بار شروع کر رکھی ہے، آپ بھی وعدہ کریں۔ نیز فرمایا کہ موطا امام مالک حفظ کر رہا ہوں، آپ تکمیل کی دعا کریں۔ ڈاکٹر غازی کا یہ علمی مزاج بجا طور پر علماے سلف کی یاد دلاتا ہے۔ اب ایسے عشاق علم، رُخِ زیبا کا چراغ جلا کر ڈھونڈے سے بھی نہ ملیں گے۔
جو سختی منزل کو سامانِ سفر سمجھے
اے واے تن آسانی ناپید ہے وہ راہی
عربی زبان وادب پر ڈاکٹر صاحب کی قدرت کے حوالے سے ڈاکٹر انصاری صاحب ہی نے بتایا کہ جب وہ عربوں کے سامنے گفتگو فرماتے تو وہ ان کی قدرتِ بیان، فصاحت وبلاغت اور استخصار علمی پہ انگشت بدنداں رہ جاتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل درالکتب العلمیہ، بیروت سے حضرت مجدد کے احوال وافکار پر شائع ہونے والی ڈاکٹر غازی ؒ کی کتاب ’’الحرکۃ المجددیہ‘‘ میں ان کے باغ وبہار قلم کے کمال کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
آج جب کہ قحط الرجال کا دور ہے، پرانے بادہ کش اٹھتے جاتے ہیں، ایک چراغ بجھتا ہے تو ظلمتوں کے بسیرے مزید طویل ہو جاتے ہیں، ہر میدان میں موثر افراد ی تیاری بند ہو رہی ہے اور ’’تبقی حثالۃ کحثالۃ الشعیر اوالتمر‘‘ کی نبوی پیشین گوئی مکمل طور پر پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ایسے میں ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا وجود ایک ابرنیساں، ایک آتش عالم افروز، ایک قلزم بے پایاں تھا۔ وہ فکرارجمند والا ایک بلند دماغ اور زبانِ ہوشمند ودلِ درد مندوالا ایک بے چین داعی تھا جو زندگی کے مختلف میدانوں میں امت کی زبوں حالی پہ وفورِ جذبات میں پکار اٹھتا تھا۔
نواے من ازاں پر سوز و بے باک و غم انگیز است
بخاشاکم شرار افتاد وبادِ صبح دم تیز است
حضرت سعید بن جبیرؓ (جو حجاج بن یوسف کے ظلم کا نشانہ بنے ) کی موت کے بارے میں میمون بن مہرانؒ اور امام احمد بن حنبلؒ جیسی شخصیات نے کہا تھا: قتل سعید بن جبیر و ما علی وجہ الارض الا ھو محتاج الی علمہ (سعید بن جبیر کی شہادت ایک ایسے وقت میں ہوئی کہ روئے زمین پہ ہر فرد ان کے علم کا محتاج تھا۔) ڈاکٹر غازیؒ دنیا سے اٹھے ہیں تو اس جملے کا اطلاق ان کی وفات پر کرنا شاید مبالغہ نہ ہو۔ معیشت و تجارت کے مسائل آپ کی بصیرت کے ضرورت مند تھے، قضاو تعلیم کا شعبہ آپ کی دقیقہ رسی کا طالب تھا، دینی مدارس کے نصاب ونظام پر گفتگو کی بات ہوتی تو نظریں ڈاکٹر غازیؒ کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ دنیا سے کیا گئے، علوم دینی ودنیوی کا ایک مفکر داغ مفارقت دے گیا، تفقہ وتدبر کا ایک دبستان بند ہوگیا، وسعت فکر ونظر کا ایک بہتا دریا سوکھ گیا، اپنی ہی ذات میں ایک انجمن اجڑ گئی۔ اے دریغا! کہ بساطِ علم ماتم گسار ہے، فکر ونظر کے افق پہ شامِ غم کی تاریکیاں بکھر گئی ہیں، انسانیت واخلاق کا ایک نمونہ نظروں سے روپوش ہوگیا ہے۔ جی ہاں!یہ مبالغہ نہیں۔ ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب نے فرمایا کہ کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو ہماری نظریں غازی صاحب کی طرف اٹھتی تھیں اور اطمینان رہتا تھا کہ ان سے مشاورت کر لیں گے، لیکن اب
شمع روشن بجھ گئی
بزمِ سخن ماتم میں ہے
ان کے مشہور محاضرات کا سلسلہ قرآن سے شروع ہوا اور دینی مدارس میں قرآن ہی کی تدریس کے حوالہ سے الشریعہ اکادمی میں ان کا محاضرہ ہونا تھا کہ وقت موعود آن پہنچا۔ آغاز و انجام میں حسن مطابقت محض اتفاق ہی نہیں خداوند قدوس کی کسی مشیت کی جانب اشارہ بھی ہے۔
ڈاکٹر غازیؒ کے علمی وفکری کمالات پر اہل علم وفکر ہی گفتگو کریں گے اور وہ اس کے اہل بھی ہیں۔مجھے تو ایک ادنی طالب علم کی حیثیت سے ملک و ملت اسلامیہ کے اس گوہر یک دانہ کے فقدان پہ ان جذبات غم کا اظہار کرنا تھا جو دل کی خاموشیوں میں تموج پید اکرتے ہیں۔
من نیز حاضر می
شوم تذکار غازی برقلم
میں عالم تصور میں ڈاکٹر غازیؒ کی مرقد پہ کھڑا ہوں اور کسی شاعر کا شعر تصرف کے ساتھ گنگنارہا ہوں۔
ایا قبر غازی! کیف واریت علمہ
و قد کان منہ البر والبحر مترعا
علم کا آفتاب عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک عالم آدمی ساری عمر علم کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہے اور شام زندگی کے قریب جب وہ سطح آب پر نمودار ہوتا ہے تو اس کے دامن میں چند سیپیاں، چند گھونگھے اور کبھی کبھار کوئی ایک آدھ موتی ہوتا ہے۔ مگر اس دنیا میں چند ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں جو فنا فی العلم ہو کر خود علم کا بحرِبیکراں بن جاتے ہیں۔ اس بحرِناپیداکنار کی تہہ میں اترنے والے غواص بیش قیمت موتیوں سے اپنے دامن کو بھر کر ایک دنیا کو مرعوب و متاثر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ متنوع اور متفرق علوم و عجائب کا ایک ایسا سمندر تھے کہ جن میں غوطہ زن ہو کر ہزاروں لاکھوں لوگ جن میں ان کے شاگرد، ان کے قارئین، ان کے سامعین اور ناظرین شامل ہیں، کسب فیض کرتے رہے۔
میں روایتی تعلیم سے فارغ التحصیل ہو کر سعودی عرب چلا گیا تھا۔ وہاں کی وزارت تعلیم میں دو اڑھائی دہائیوں تک تدریسی فرائض انجام دیتا رہا۔ اس دوران میں ڈاکٹر محمود احمد غازی کی شخصیت، ان کی بعض کتب اور دین میں راہ اعتدال اختیار کرنے جیسے ان کے کارناموں سے آگاہ ہو چکا تھا مگر سابق جسٹس خلیل الرحمان خان اور غازی صاحب کی دعوت پر پاکستان آ کر نیشنل اسلامی یونیورسٹی میں خدمت کا موقع ملا۔ اس دوران غازی صاحب کی چشم التفات مجھ پر کھلتی گئی اور ان کے ساتھ میرے تعلقِ خاطر میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور جوں جوں قربت بڑھتی گئی، تو ں توں ان کی عظمت کا نقش میرے دل پر مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ ان کی بیکراں شخصیت اور ان کے عظیم علمی و دینی کارناموں پر غور کرتا ہوں تو سمجھ میں نہیںآتا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد حافظ احمد فاروقی کی توجہ، ان کی والدہ کے حسن تربیت اور ان کے اساتذہ کے فیضان نظر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان کی والدہ آج بھی حیات ہیں اور ان کے برادر اصغر پروفیسر ڈاکٹرمحمدالغزالی کے بقول: بھائی صاحب اپنی وزارت، یونیورسٹی کی صدارت، اپنی خطابت و کتابت اور اپنی گوناں گوں مصروفیات کے باوجود والدہ صاحبہ کے سامنے آخر دم تک اقبال کے طفل سادہ کی تصویر بنے رہے۔ بقول علامہ اقبال
علم کی سنجیدہ گفتاری، بڑھاپے کا شعور
دنیوی اعزاز کی شوکت، جوانی کا غرور
زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم
صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم
مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی حافظِ قرآن بھی ہیں۔ ان کے ڈرائیور مولوی محمد یوسف نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی میرے ساتھ شہر کے اندر یا شہر سے باہر سفر کرتے، زیادہ ترقرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ بعد میں جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تھانہ بھون کے خاندان فاروقیہ کی روایات کے مطابق صرف آٹھ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ حفظ قرآن کے بعد انہوں نے عربی زبان و ادب میں کئی امتحانات امتیاز کے ساتھ پاس کیے اور ایک دینی مدرسے سے درس نظامی مکمل کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ عربی کے علاوہ انہیں فارسی، انگریزی اور اردو زبان پر بھی مکمل عبور تھا۔ اردو تو ان کی مادری زبان تھی۔ ایک بار میں نے غازی صاحب سے پوچھا کہ آپ کاتعلیمی پس منظر تو عربی مدارس کا ہے، مگر آپ عام علماء کرام کے برعکس عربی بلکہ انگریزی بھی بڑی روانی سے بولتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ کراچی کے جس دینی مدرسے میں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا، وہاں مصری اساتذہ تھے جو بیک وقت محبت اور شوق سے ہمارے ساتھ رات دن عربی میں گفتگو کرتے، اس لیے میری عربی بول چال بہت رواں ہے۔ کہنے لگے کہ ابتدا میں مجھے انگریزی سے زیادہ دلچسپی نہ تھی مگر ایک رات زمانہ طالب علمی کے دوران میں نے سوچا کہ انگریزی سیکھے بغیر چارہ نہیں۔ اگلے روز میں نے فٹ پاتھ سے انگریزی گرائمر کی ایک پرانی کتاب خریدی اور پھر چل سوچل۔ میں نے انگریزی پڑھنا، بولنا اور لکھنا شروع کردی اور چند مہینوں میں میری استعداد اور میرا اعتماد اتنا بڑھ گیا کہ میں انگریزی میں تقریریں کرنے لگا۔
غازی صاحب نے تدریس کا آغاز پہلے راولپنڈی کے مدرسہ فرقانیہ میں عربی پڑھانے سے کیا۔ پھر وہ مدرسہ ملیہ میں درس وتدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر غازی صاحب نے خود ایک بار مجھے بتایا تھا کہ میرے والد گرامی کو مولانا گلزاراحمد مظاہری ؒ نے لاہور آنے اور علماء اکیڈمی کا ڈائریکٹر بن جانے کی پیش کش کی تھی۔ غازی صاحب نے بتایا کہ وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے درمیان افہام و تفہیم کے لحاظ سے اس آئیڈیل کو بہت سراہتے تھے مگر وہ بوجوہ اس پیشکش کو قبول نہ کر سکے اور پھر اسلام آباد ہی ان کی علمی و دینی سرگرمیوں کی جولان گاہ بن گیا۔ ندوۃ العلماء لکھنو اور جامعہ ملیہ دہلی سے لے کر انٹر نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد تک تقریباً ڈیڑھ صدی سے دنیاوی علوم یکجا کرنے کے لیے روشن خیال علماء کرام نے بہت کاوشیں کیں اور اس کے لیے کئی پروگرام وضع کیے۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اس دینی و دنیاوی یکجائی کی ایک بہترین مثال اور ماڈل ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا بہت سا خونِ جگر اس گلشن کی آبیاری میں صرف ہوا ہے۔ وہ اس یونیورسٹی میں پہلے تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر وہ ڈائریکٹر دعوۃ اکیڈمی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ نائب صدر جامعہ اور بعد ازاں صدر جامعہ کی حیثیت سے یونیورسٹی کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی دوران وہ تین برس تک وزیر مذہبی امور بن گئے۔ وزارت اور اسلامی یونیورسٹی کی صدارت کے بعد وہ یونیورسٹی میں ایک بار پھر عام پروفیسر کی حیثیت سے درس وتدریس میں مشغول ہو گئے۔
اگرچہ ہماری ملکی روایات کے مطابق ایک بار کوئی شخص اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکا ہو تو پھر وہ عام افسر یا استاد کی حیثیت سے فرائض انجام نہیں دیتا۔ یونیورسٹی کی نائب صدارت، پھر صدارت اور اس کے بعد وزارت کے بعد نہ ان کے پاس کوئی پلاٹ تھا، نہ کوئی بنگلہ اور نہ ہی ذاتی کار تھی۔ ان کے پاس ایک مشترکہ خاندانی گھر تھا جس میں دوسرے افراد خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ صدارت کے بعد سرکاری گاڑی واپس کرنے کے بعد انہوں نے المیزان اسلامی بنک کے ذریعے قسطوں پر گاڑی خریدی جسے وہ خود چلاتے تھے۔ جب کہیں دور جانا ہوتا یا گھر والوں کو ضرورت ہوتی تو وہ اپنے پرانے ڈرائیور کو جو اس وقت میرے ساتھ کام کر ر ہے تھے، فارغ اوقات میں بلاتے اور خدمت کا اسے معاوضہ ادا کرتے۔ کل وقتی ڈرائیور افورڈ کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ دیانت وامانت کے اعتبا ر سے غازی صاحب کا کردار مثالی تھا۔ یونیورسٹی صدارت سے فارغ ہو کر تقریباً آٹھ نو ماہ تک وہ شریعہ کے شعبے میں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے اور پھر قطر یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں پر ہی انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے شریعت کورٹ میں جسٹس کی ذمہ داری کی پیش کش ہوئی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے قرآنیات، اقبالیات، اسلامی سیاسیات ومعاشیات ، سیرت وحدیث پاک وغیرہ پر درجنوں کتابیں اردو اور انگریزی میں لکھیں، تاہم عربی زبان اور فقہ اسلامی ان کے خاص موضوعات تھے جن میں انہیں سند کا درجہ حاصل تھا۔ میرے استاذ گرامی ڈاکٹر خورشید احمد رضوی ، غازی صاحب کے بے تکلف دوست تھے۔ انہوں نے بتایا کہ غازی صاحب پاکستان میں عربی زبان کے دو چار عالموں میں سے سرفہرست تھے۔
ایک زمانے میں غازی صاحب فتنہ قادیانیت کے رد میں جنوبی افریقہ کی عدالت میں مسلمانوں کے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوتے رہے۔ انہوں نے وہاں دو اڑھائی ماہ قیام کیا تھا اور قادیانیت کی حقیقت کو آشکارا کیا۔ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ اور اتحاد بین المسلمین غازی صاحب کی زندگی کا مشن تھا۔ وہ جس بین الاقوامی یا اسلامی کانفرنس میں جاتے، وہاں اس بات کا تذکرہ ضرور کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آمین۔
(بشکریہ نوائے وقت لاہور، یکم اکتوبر ، ۲۰۱۰ء)
دگر داناے راز آید کہ ناید
حافظ ظہیر احمد ظہیر
مخدومی، استاذ ذی وقار حضرت مولانا ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی مدظلہ العالی نے علالت کے باعث اپنے قابلِ فخر بھتیجے مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر، جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی کے حوالے سے کچھ لکھنے کا حکم فرمایا۔ تعمیل ارشاد میں اس اعتراف کے ساتھ کہ آپ کا ادراکِ نسبت یا ادراکِ کمالات میرے جیسوں کا منصب ہرگز نہیں ہے، راقم اثیم چند سطریں قارئین ’’الشریعہ‘‘ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کررہا ہے۔
موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کومفر نہیں، لیکن جو لوگ کسی نظریے اور مشن کے لیے تادمِ آخر ان تھک محنت اور لگن سے کام کرتے رہیں، وہ کتنی ہی طویل عمر کیوں نہ پائیں، ان کی جدائی قبل از وقت ہی محسوس ہوتی ہے۔
ڈاکٹرصاحب ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ آبائی وطن علم و حکمت کی دانش گاہ ’’تھانہ بھون ‘‘ ٹھہرا۔ آپ کے والد گرامی حافظ محمد احمد فاروقیؒ صاحب کی بیعت وارادت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی سے قائم تھی اور ان کو حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل حضرت مولانا فقیر محمد پشاوریؒ اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ مہاجر مدنی سے اجازت بیعت اور خلافت بھی عنایت ہوئی۔ ڈاکٹرصاحب نے حصول تعلیم کے لیے شیخ المحدثین علامہ ظفرؒ احمد عثمانی کی خدمت میں زانوئے تلمذ تہہ کیے۔ عین ممکن ہے کہ بعض حضرات کا خیال شاید یہ بھی ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی اٹھان میں ان کے اپنے ذاتی کردار، انفرادی کوشش، اپنے مشن کے ساتھ والہانہ لگاؤ اور اس کے حصول کے لیے ان تھک جدوجہد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس سے انکار نہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کی تعمیر و ترقی میں عظیم نسبتوں، اکابر و اسلاف کے اعتماد اور اساتذہ و شیوخ کی دعاؤں کو روح کی حیثیت حاصل ہے۔
موصوف قدیم و جدید علوم کے متبحر عالم دین، اسلامی یونیورسٹی کے سابق صدر، فیصل مسجد کے سابق خطیب اور شرعی عدالت کے جج تھے۔ رب العزت نے ان مناصبِ جلیلہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ظاہری اور باطنی نسبت وکمالات سے بھی نوازرکھا تھا۔ آپ متنوع صفات اور مجموعہ کمالات شخصیت کے مالک تھے ۔آپ ہمارے دور کی ان چند ممتاز ویگانہ شخصیات میں سے ایک تھے جن کے دل میں دین فطرت کو عالم گیر مذہب کے طور پردیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے اور وہ لوگ اس تڑپ کو سکون دینے کے لیے اپنی خداداد صلاحیتوں اور گوناگوں اوصاف و کمالات کے ساتھ جہدِ مسلسل اور سعی پیہم سے بھرپور کام لیتے ہیں۔ موصوف ڈاکٹر صاحبؒ کی تمام صفات کوحیطہ تحریر میں لانا ایک طویل وقت اور خاصی محنت کا متقاضی ہے، لہٰذا میں ان کی چند ایک خدمات کا اجمالی سا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ۔
قارئین گرامی !اگر آپ ڈاکٹر محمود احمد غازی کو آج کے دور میں نہیں، مسلمانوں کے مثالی دورِ عروج کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزادؒ کے ایک خط جو انہوں نے اپنے کسی عزیز کو لکھا تھا کا اقتباس ضرور پڑھیں ۔ فرماتے ہیں:
’’آپ کے لیے بہترین زندگی علمی زندگی ہے، اس شکل و طرز کی جس کانمونہ سلف صالح کے حالات سے ملتا ہے۔ علماء اسلام کے حالات پڑھیے۔ درس و تدریس، وعظ و ارشاد اور تصنیف و تالیف تینوں چیزوں کو بیک وقت کرتے تھے اور اس طرح ایک زندگی میں تین عظیم الشان خدمات انجام دیتے تھے۔ عوام کی اصلاح وعظ وتذکیرسے، مستقبل کے لیے تیاری دروس تدریس اور علم و مذہب کی خدمت دائمی تصنیف و تالیف سے ۔ ابن جوزیؒ مصنف ہیں، مستنصریہ کے صدر مدرس ہیں اور جامعہ رصّافہ کے واعظ۔ غزالیؒ مدرسہ طوس کے معلم، سو کتابوں کے مصنف اور جامعہ طوس کے واعظ۔ علماء اسلام کی زندگی کے لیے تو یہ طبیعت ثانیہ ہوگئی تھی۔ ایک شخص آپ کو نہیں ملے گئے جو اپنی زندگی میں یہ تینوں مشغلے نہ رکھتا ہو۔ جب سے یہ طبقات الگ ہوئے، سلسلہ ہدایت اور علم مفقود ہوکے رہ گیا۔‘‘
اس تحریر کی روشنی میں ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے قرونِ اولیٰ کی یاد تازہ فرمادی تھی ۔ ہم مختصراً ڈاکٹر صاحب کو ایک مقرر،مصنف اور مدرس کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔
بحیثیت مقرر
حضرت ڈاکٹر صاحبؒ پلند پایہ داعی اور مقرر تھے۔ آپ اردو، عربی، انگریزی تینوں زبانوں میں لکھنے پڑھنے پر خوب قادر تھے اور اس کے علاوہ فرانسیسی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کی تقاریر جہاں قوتِ استدلال،نکتہ شناسی و نکتہ آفرینی کا بہترین مرقع ہوتیں، وہاں ایسی قیمتی معلومات کے خزینے بھی ہاتھ آتے جن کو تلاشِ بسیار اور کئی کتابوں کی ورق گردانی کے بعد بھی شاید حاصل نہ کیا جاسکے۔ آپ نے دین فطرت کی دعوت میں جو زبان استعمال کی ہے، وہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ اور موعظہ حسنہ کی بہترین عملی تفسیر ہے ۔
قرآن کریم، حدیث مبارکہ، سیرت پاک، فقہ اسلامی، شریعت اور معیشت و تجارت کے موضوعات پر ان کے خطابات محاضراتِ قرآنی، محاضراتِ حدیث، محاضراتِ سیرت،محاضراتِ فقہ کے نام سے کتابی شکل میں طبع ہوچکے ہیں۔ یہ مجموعہ جات آپ کے علوم و معارف کا نچوڑ ہیں۔ بقول ڈاکٹر صاحب ’’ان کے خطابات کی زبان تحریری نہیں، تقریری ہے۔ اندازِ بیان عالمانہ اور محققانہ نہیں، داعیانہ اور خطیبانہ ہے ۔‘‘
آپ نے ۸۰ء کی دہائی میں جنوبی افریقہ کی عدالت میں عقیدۂ ختم نبوت کے حوالے سے مرزائیوں کے مقابلے میں گفتگو کے لیے پاکستان کے دیگر چوٹی کے اہل علم کے ساتھ ایک تاریخی سفر فرمایا۔ اس وفد میں مفکر اسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ، علامہ ڈاکٹر خالد محمودمدظلہ ، ڈاکٹر اسحاق ظفر انصاری مدظلہ اور دیگر جید علماء اسلام شامل تھے۔ اس سفر کا ذکر حضرت مفتی تقی عثمانی نے اپنے سفر نامہ ’’جہانِ دیدہ‘‘ میں تفصیل سے فرمایا ہے ۔ استاذ محترم علامہ ڈاکٹر خالد محمود مدظلہ العالی نے راقم کو بتایا کہ ڈاکٹر غازی صاحب نے میدانِ مناظرہ کا آدمی نہ ہونے کے باوجود اس مقدمہ میں اس طرح بھرپور منطقی استدلالات کے ساتھ اور زوردار انداز میں ختم نبوت پر گفتگو فرمائی کہ بس انھی کا خاصہ تھا۔
حضرت کے خطبات میں قابل ذکر چیز آپ کی آفاقی نظر تھی۔ آپ نے دنیا بھر کے دورے کیے بلکہ عمر کا ایک طویل حصہ اسی دعوت کے کام میں گزرا۔ اس کثرت اسفار نے ایسا ذوق پیدا کررکھا تھا کہ آپ جب بھی کسی مسئلہ پر بولتے، اگر چہ آپ کے سامنے اردو دان طبقہ ہوتا مگر محسوس یوں ہوتا تھا کہ آپ صرف موجود سامعین کو نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کو دین فطرت کی دعوت دے رہے ہیں ۔
بحیثیت مدرس
اسلامی علوم کی دنیا کے دیگر علوم پربرتری ثابت کرنے کے لیے علوم کے تقابلی مطالعے اور جدید تعلیم کے سحر میں گرفتار افراد کا اسلامی علوم پر اعتماد بحال کرنے اور قرآن وسنت، فقہ اسلامی پر اعتراضات کے کافی و شافی جوابات دینے میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تدریس کے دوران یہ آپ کا ایک نمایاں وصف تھاکہ آپ نے جدید دور کی تمدنی اور معاشرتی خرابیوں کی اصلاحِ احوال کے لیے بہتر اور مؤثر لائحہ عمل کی نشاندہی کی۔ آپ نے مغربی نظام تعلیم کی پیدا کردہ خرابیوں کا پوری طرح ادراک کر کے اپنے شاگردوں میں اسلامی روح منتقل کرنے کی ہر ممکن کوشش فرمائی۔ آپ کا حلقہ درس و تدریس عوام الناس یا مذہبی طبقے کی بجائے چونکہ زیادہ تر عصری تعلیم کے حامل افراد پر مشتمل تھا، لہٰذا آپ نے مسلم معاشرے کے بالائی طبقہ کی ذہنی الجھنوں کو بڑی گہرائی سے سمجھا اور پھر ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان سے بات کرنے کی خوب استعداد اور مہارت پیدا کی۔ دوران تدریس آپ کے لیکچرز وسیع و عمیق مطالعہ اور علم و تحقیق کا محور ہوتے تھے۔
بحیثیت مصنف
اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ تقریر اور درس و تدریس کی مستقل ذمہ داریوں کے ساتھ تصنیف کے مستقل شعبہ سے وابستگی کس قدر مشکل امرہے اور پھر صرف روایتی تصنیف و تالیف نہیں بلکہ فکری ، نظریاتی اور تخلیقی تحریر کا میدان کسی اور مصروفیت کے لیے کہاں چھوڑتا ہے۔ لیکن رب العزت نے جن ہستیوں سے کام لینا ہو، ان کے وقت کے لمحات بھی بابرکت بن جاتے ہیں۔ وقت ان کے ساتھ سمجھوتہ کرکے گزرتا ہے۔ تصنیف کے حوالے سے آپ کے غیر معمولی شاہکار منصہ شہود پر آکر اہل علم و فن سے داد حاصل کرچکے ہیں جن میں ادب القاضی ،قانون بین الممالک، اسلامی بینکاری: ایک تعارف،اسلام اور مغرب تعلقات، مسلمانوں کا دینی و عصری نظام تعلیم، اصول فقہ و علم اصول فقہ، (اصول فقہ) تقنین، (اصول فقہ ) پاکستان میں قوانین کی اسلامائزیشن، (اصول فقہ) قواعد کلیہ، قواعد کلیہ اور ان کا آغاز و ارتقا، ان کی علمی ثقاہت کا منہ بولتا ثبوت ہیں ۔
ڈاکٹر صاحب کا قلم فکر انگیز تحریر لکھنے کے سوا کچھ اور لکھنے کا عادی ہی نہ تھا۔ آپ کی تحریروں کا مطمح نظر امت میں ابتدائی صدیوں میں اسلامی علوم کی تدوین پر حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، محدثین، مفسرین، فقہا اور مؤرخین کی خدمات کا وسیع مطالعہ تھا۔ قدیم و جدید مفکرین کے فکر کی نوعیت کو سمجھ کر ان کے مثبت اور کمزور پہلوؤں پر گہری نگاہ رکھ کر مسلمانوں کے مستقبل کو ماضی سے جوڑتے ہوئے امت کو اپنی نئی فکر اور نئی جماعت و دائراتی خول سے داغدار اور منتشر نہ ہونے دینا آپ کی تصنیفی زندگی کا نصب العین تھا۔
چند دیگر صفات
یہ تو ایک خاکہ تھا جس میں آپ کی سیرت کے چند نمایاں گوشے اجمال کے ساتھ ذکر ضرور کیے ہیں، لیکن پھر بھی بہت کچھ باقی ہے اور باقی رہے گا ۔ وہ بہت بڑے قد کے آدمی تھے۔ خدا نے ان کو فقر، درویشی جیسی اعلیٰ صفات سے بھی نوازا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے علمی کارناموں اور بے مثال دینی خدمات سرانجام دینے کے باوجود اپنے آپ کو فقیر سمجھتے تھے، کیونکہ آپ باضابطہ عالم دین اور صوفی تھے۔ عالمِ ربانی کے الفاظ ان پر صادق آتے تھے۔ علمی تبحر، وسعت مطالعہ اور غیر معمولی ذہانت و ذکاوت، عالمی دنیا میں ایک نامی گرامی شہرت کے باوجود آپ ہمیشہ مجسمہ انکسار و عاجزی رہے اور من تواضع للّٰہ رفعہ اللّٰہ کے سانچے میں ڈھلے حقیقی پیکر انسانی تھے۔ بقول شیخ سعدی ؒ
تواضع ز گردن فروزاں نکوست گداگر تواضع کند خوئے اوست
’’بلند مرتبہ لوگوں سے تواضع بھلی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اگر فقیر اور گداگر تواضع کرتا ہے یہ اس کی مجبوری ہے ۔‘‘
عاجزی اور انکساری ان کا نمایاں وصف تھا۔ تھانوی مکتبِ فکر کی تربیت، اصول پسندی اور سلیقہ مندی ان کے چہرہ بشرہ سے عیاں تھی ۔
ڈاکٹر صاحب کی راہِ زندگی میں کچھ مشکل گھڑیاں اور کٹھن مراحل بھی آئے جو ہر بڑے آدمی کی راہ میں اسپیڈ بریکر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسد و عناد کے بھی کچھ نشتر چلانے کی کوشش کی گئی تو درویش صفت ڈاکٹر محمود غازی یہ کہہ کر سب کچھ نظر انداز کرگئے۔ بقول شخصے :
کسی شاخِ سرنگوں پہ رکھ لوں گا چار تنکے
نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ
پاکستان میں سودی بینکاری سے نجات کے لیے جن لوگوں نے کا م کیا ہے، خصوصاً جب معاملہ سپریم کورٹ کے اپیلٹ بینچ میں گیا اور پھر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس مسئلے کا بخوبی جائزہ لیا، اس سارے مقدمے کا ایک بنیادی کردار ڈاکٹر صاحب بھی ہیں۔ آپ نے اس موقع پر شیخ الاسلام جسٹس (ریٹائرڈ) مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی کا دست وبازو بن کر اپنے جوہر دکھائے ۔
دینی و مذہبی حلقوں کا ناقابل تلافی نقصان
ڈاکٹر صاحب کی رحلت سے دینی و علمی حلقوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ آپ زمانہ جدید کی تمام تر اصطلاحات اور اسلوب سے نہ صر ف واقف تھے، بلکہ اس معاملے میں ایک خاص تجربہ رکھتے تھے اور اپنے پیغام کو مغرب زدہ طبقے کے ذہنوں میں بڑی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ اتارنے کا ڈھنگ بھی جانتے تھے ۔ اگر یہ کہا جائے تو بجاہوگا کہ اہل مدارس اور تجدد پسندی کے دلدادہ لوگوں کے درمیان ڈاکٹر صاحب ایک پل کا کردار ادا کرسکتے تھے، کیونکہ دونوں طرزِ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ مدارس اور کالجز، یونیورسٹیز کے مزاج و ماحول سے آپ گزر چکے تھے۔ جدید تعلیم یافتہ فرد جو مولوی اور مدرسہ سے نہ معلوم کیوں خوفزدہ رہتا ہے، آپ اس طبقے کے لوگوں کو دین اور دینداروں کے ساتھ جوڑنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اہل مدارس نے اس سلسلے میں اب ان سے رہنمائی لینا شروع کر دی تھی، لیکن قضا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آپ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون)۔
ہماری معلومات کے مطابق اس سلسلے میں سب سے مؤثر قدم اٹھانے میں پہل دینی و عصری علوم کے حسین امتزاج کے حامل جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور نے اپنے تدریب المعلمین کے پروگرام منعقدہ ۱۳، ۱۴ فروری ۲۰۱۰ء کے ذریعے کی۔ (یہ پروگرام اس قدر کامیاب رہا کہ اس کے بعد دو مرتبہ علماء و طلبہ کے بھر پور اجتماع کی شکل میں منعقد ہوچکا ہے ، فالحمد للہ علیٰ ذالک)۔ اس میں ملک کے نامور علماء اور اسکالرز، پروفیسر حضرات کے بھرپور علمی و تربیتی بیانات ہوئے جوکہ مجموعہ مقالات کے نام سے دو جلدوں میں شائع ہوچکے ہیں۔ اصحابِ ذوق کے لیے یہ ایک نادر اور گراں قدر علمی سوغات ہے۔ ان تمام بیانات میں ڈاکٹر صاحبؒ کا خطاب انتہائی ایمان افروز ، فکر انگیز اور کلیدی اہمیت کا حامل ہے ۔ حضرات اکابر جامعہ، شیخ الحدیث مولانا مشرف علی تھانوی مدظلہ العالی اور حضرت ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی نے، جوکہ موصوف غازی صاحب کے رشتے میں چچا بنتے ہیں، آپ کے لیے ’’دینی و عصری تعلیم کا امتزاج‘‘ کا عنوان تجویز کیا۔ ویسے تو آپ کا سارا خطاب ہی پڑھنے اور سننے کے قابل ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر اس خطاب کا مرکزی خیال اور روحِ بیان ڈاکٹر صاحبؒ کی اپنی زبان سے ہی بیان کردہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:
’’بعض حضر ات بعض علماء کر ام جب اس پر تامل کا اظہارکرتے ہیں تو ان کاتامل بالکل بجاہوتاہے۔ ان کاتامل اس لیے ہوتاہے کہ بعض لوگ اسلامی علوم کو خادم اور عصری علوم کو مخدوم بناکے ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اسلامی تاریخ میں کسی بھی عصری علم یاعصری فن سے جب استفادہ کیا گیا تو اسلامی علوم اور اسلامی ثقافت اور تہذیب کے خادم کے طور پر اس سے کام لیا گیا اور اس خادم نے اسلامی علوم کو مخدوم بناکر ان کی خدمت کی ۔ یہ آپ کو علم طب میں بھی نظر آئے گا، تفسیر میں بھی ،حدیث میں بھی، فقہ میں بھی، اصول فقہ میں بھی ،کلام میں بھی، حتی کہ تصوف میں بھی۔ تصوف جیسے فن کی کتابیں جو خالص روحانیات کامیدان ہے، اس کو بھی اتنے مضبوط عقلی استد لال سے بیان کیاگیاہے۔ یہیں اس کتب خانے میں ہوں گی، آپ دیکھ لیں۔ ’’تربیۃ السالک‘‘ دو بڑی ضخیم جلدیں ہیں اوربہت ساری کتابیں ہیں جن کے میں نام لوں گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی ۔ وہ سب کی سب عقلی استدلال کی بنیاد پرہیں، اس لیے یہ بات کہ عصری علوم سے استفادہ کوئی نئی چیزہے جس کی آج بعض لو گ دعوت دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ عصری علوم سے استفادہ ہر دور میں مسلمان اہل علم کرتے آئے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ کہ عصری علوم پر ناقدانہ نظررکھتے ہو ں، مقلدانہ نہیں۔ مقلدانہ نظر توخطر ناک ہوتی ہے۔ ناقدانہ نظر عصری علوم پر رکھتے ہوں اور اسلامی علوم سے مجتہدانہ طور پر واقف ہوں تاکہ عصری علوم کو، جو بھی جس زمانے کے علوم ہیں، ان کو اسلام کی خدمت کے لیے اور اسلامی علوم وفنون کو نئے انداز سے مرتب اور مدون کرنے کے لیے بیان کریں۔
آج کے سیاق وسباق میں عصری علوم سے کیامراد ہے؟ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں،ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے ملک کے ہیں ،ان سے میں نے ایک مرتبہ بات کی،جب میں انتظامی طور پر بعض معاملات سے وابستہ تھا تو میں نے یہ بات کی عصری علوم کی تو انہوں نے بہت غصے سے مجھ سے پوچھا کہ کیا انجینئر نگ کالج میں مولوی تیار ہوتے ہیں تو پھر مدرسوں میں انجینئر کیوں تیا ر ہوں؟ یہ بالکل خلط مبحث ہے۔ عصری علوم وفنون سے استفادہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایک محدث کو حدیث کی درسگاہ سے اٹھاکر انجینئر بنا دیا جائے، ایک فقیہ کو دار الافتاء سے اٹھا کر کہا جائے کہ تم میڈیکل ڈاکٹر ہوجاؤ۔ اگر کوئی یہ سمجھتاہے تو غلط سمجھتاہے۔ محدث کو محدث ہی رہنا چاہیے، لیکن محدث ایسا ہو جو علم حدیث پر ماہرانہ،مجتہدانہ بصیرت رکھتاہو ، اپنے وقت کا انور شاہ کشمیری ہو، اس طرح کا محدث ہو، لیکن علم حدیث پرجو آج اعتراضات کیے جارہے ہیں، آج کا تعلیم یافتہ آدمی جن اسباب سے علم حدیث کے بعض پہلوؤں پر شبہات رکھتاہے،ان شبہات کو سمجھنے کے لیے بعض چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ شبہات نہیں جانتا، اگر وہ ان اعتراضات کے منشا سے واقف نہیں ہے کہ وہ اعتراضات کیوں پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہ ان کا جواب نہیں دے سکتا۔
یہ بات میں بہت ادب سے، لیکن جرأت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام فتویٰ دیناہے ۔ فتوے سے کسی کا ذہن نہیں بنتا۔فتویٰ اس کے لیے ہوتا ہے جو دین پر عمل کرناچاہے اور آپ سے آکر پوچھے۔ جو گمراہ ہے، شہر میں گمراہی پھیلارہاہے، آپ اس سکے خلاف فتویٰ دے کر کیا کرلیں گے ؟ آپ کے فتوے سے وہ گمراہی سے باز آجائے گا ؟میں مثالیں دوں گا تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ ہزاروں گمراہیاں جن کے خلاف فتوے آئے اور یہ سمجھا علماء کرام نے کہ ہم نے فتویٰ دے دیا، ہمار اکام ختم ہوگیا، لیکن وہ کام ختم نہیں ہوا۔ اگر گمراہی اس وقت ایک گملے میں تھی تو آج جنگل بن گئی ہے، کانٹے دار درخت اس نے پیدا کر دیے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ وہ گمراہی کیوں پیدا ہوئی اور کہاں سے پیدا ہوئی ؟اور وہ سوالات جو پیدا ہورہے ہیں، کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟
میں پوری دنیا میں جاتا رہتا ہوں۔ مختلف ملکوں میں جانے کا پچھلے ۳۰ سال میں موقع ملتا رہا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ انتہائے مشرق میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے دن میں پہلی مرتبہ، ’’جزائر فجی‘‘ وہاں کا ایک عام تعلیم یافتہ شخص اور امریکہ کی انتہائی مغربی ریاست ’’سان فرانسسکو‘‘ کا ایک عام تعلیم یافتہ شخص ایک ہی طرح کے اعتراضات کرتاہے اسلام پر۔ پیرس میں جائیں، کسی سے بات کریں، وہ بھی وہی اعتراض کرے گا۔ ساؤتھ افریقہ میں جائیں تووہ بھی وہی اعتراض کرے گا۔ پاکستان میں کسی بڑے جدید تعلیمی ادارے میں جائیں ،لمز میں جائیں تو وہاں بھی اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے ۔ سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ یہ ایک ہی طرح کے سوالات اور ایک ہی طرح کے اعتراضات اور ایک طرح کے شبہات پوری دنیا میں کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تہذیب اور وہ فکری استیلا جو مغرب سے آیا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس استیلا کی وجہ سے وہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہاں بیٹھ کے فتویٰ جاری کر دیں کہ فلاں چیز گمراہی ہے تو جو لوگ پہلے سے گمراہی سمجھتے ہیں، وہ مزید یقین سے گمراہی سمجھنے لگیں گے، لیکن جو اسے گمراہی نہیں سمجھتے، وہ آپ کے فتوے سے اسے گمراہی نہیں سمجھنے لگیں گے۔ وہ اس پہ بدستور قائم رہیں گے، جیسا کہ میں سینکڑوں مثالیں دے سکتاہوں کہ لوگ قائم رہے اور آج بھی قائم ہیں، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس دور کے محاورے کو سمجھنے کے لیے اور امام ابویوسف کا یہ جملہ میں کئی مرتبہ دہر اچکا ہوں : ’’من لم یعرف اھل زمانہٖ فھو جاہل‘‘، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں جانتا، وہ جاہل ہے ، یعنی اس کا علم قابل اعتبار نہیں ۔ لہٰذا جس زمانے کے ماحول میں آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ’’وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ‘‘، لسان قوم میں صرف اردو یاپنجابی یاانگریزی شامل نہیں ہے۔ لسان میں وہ پورا تہذیبی پس منظر بھی شامل ہے جو ا س زبان میں شامل ہوتاہے۔ زبان محض کوئی vehicle نہیں ہے، محض کوئی وسیلہ نہیں ہے خیالات کے انتقال کا یابیان کرنے کا۔ ہرلفظ کے پیچھے پوری تاریخ اور پوری تہذیب اور پورا فکر ہوتا ہے۔ وہ فکر اور تہذیب خود بخود اس لفظ کے ساتھ آتی ہے۔‘‘
یہ تھی ایک جھلک ڈاکٹر صاحب کے ذہنی اور فکری نقطہ نظر کی۔
قارئین گرامی ! اپنے بزرگوں کا تذکرہ اس غرض سے ہم اصاغر تو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہیں کردار و عمل کی کسوٹی پر جانچا اور کشف و کرامات کے ترازو میں تو لا جائے۔ ہرگز نہیں! بلکہ ان کے باعظمت کردار کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر خود سے سوال کرنا مقصود ہے کہ میں اس شفاف آئینے میں کیسا لگتا ہوں ؟ اور یقین کی حدتک یہ امید تو ہے ہی کہ:
احب الصالحین ولست منھم
لعل اللہ یرزقنی الصلاحا
آپ کی رحلت سے پیدا ہونے والا خلا تادیر اہل علم کے زخموں کو تازہ کرتا رہے گا اور اس درد کی کسک امت مسلمہ عرصہ دراز تک محسوس کرتی رہے گی ۔ دعا ہے کہ رب العالمین اپنے خزانہ قدرت سے ہمیں آپ کا نعم البدل عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔
ایک نابغہ روزگار شخصیت
سبوح سید
۲۶ ستمبر کو دنیا بھر میں عارضہ قلب کا عالمی دن منایا جا رہا تھا۔ ملک بھرمیں اس بیماری کے علاج اور تدارک کے لیے عوام میں شعور بیدا ر کرنے کی مہم جاری تھی اور ٹیلی ویژن کے چینلز پر رپورٹرز بیماری سے متاثرہ افراد کی زندگیوں پر اور ڈاکٹرز کی ہدایات پر رپورٹس پیش کر رہے تھے۔ میں بھی جیو نیوز پر عارضہ قلب کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ ایک میسج پڑھا توپاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے سابق صدر اور معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمود احمد غازی حرکت قلب بندہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ دو پہر دو بجے ایچ الیون قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ میں نے اس خبر کی تصدیق کے لیے دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اور فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمن صاحب کو فون کیا تو انہوں نے انتہائی دکھی انداز میں اس خبر کی تصدیق کی۔ میں نے کئی لوگوں کو اس افسوسناک خبر کے پیغامات بھیجے۔ شیخ زایداسلامک سنٹر جامعہ پشاور کے ڈائریکٹر اور میر ے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر دوست محمد خان صاحب نے فون پر کیا خوب بات کہی کہ ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ عالم کی موت پورے جہاں کی موت کیسے ہوتی ہے! ان کا کہنا تھا کہ ان کی گزشتہ ہفتہ ڈاکٹر غازی صاحب سے فون پر بات ہوئی جس میں انہیں شیخ زاید اسلامک سنٹر میں ’’خطبات خیبر‘‘ کے نام سے دس روزہ لیکچر دینے کی دعوت دی گئی جو انہوں نے قبول کرلی تھی۔
ان کی گفتگو مجمع کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ ان کی فکر قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور ان کی سیرت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھلکتا تھا۔ کتب احادیث ، تاریخ اور فقہ کے حوالے انہیں ازبر تھے۔ جن لوگوں نے انہیں سنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ گفتگو کے اسلوب وہنر اور زبان وبیان کی خوبیوں سے بدرجہ کمال آشنا تھے۔
پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی ۱۸؍ستمبر ۱۹۵۰ء کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین کا تعلق حضرت اشرف علی تھانویؒ کے گاؤں تھانہ بھون ہندوستان سے تھا۔ آپ کے والد محمد احمد دفتر خارجہ میں ملازمت کرتے تھے۔ تقسیم کے بعد کراچی آئے، تاہم ملازمت کے سلسلے میں انہیں اسلام آباد منتقل ہونا پڑا۔ کراچی میں ڈاکٹر محموداحمد غازی مدرسہ عربیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں درجہ خامسہ تک مولانا یوسف بنوریؒ کے شاگرد رہے، تاہم والد کے اسلام آباد منتقل ہوجانے کے بعد وہ راولپنڈی میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کے قائم کردہ ادارے تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں داخل ہو گئے اور یہیں سے دورہ حدیث کیا۔ دینی علوم کے بعد آپ نے عصری تعلیم کا رخ کیا۔ انہوں نے باقاعدہ اسکول نہیں پڑھا۔ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کے امتحانات پرائیویٹ دیے۔ ڈاکٹر غازی بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے اور تعلیم کے حصول میں مگن رہے۔ آپ کے بھائی ڈاکٹر محمد الغزالی نے بتایا کہ انہیں کھیل کود سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی اور عمر بھر پڑھنے لکھنے کی دھن میں مگن رہے۔ آپ نے شاہ ولی اللہ کی معاشی تعلیمات اور فلسفے کی نشاۃ ثا نیہ پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔ آپ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور اردو پر عبور رکھتے تھے۔
آپ کی عربی زبان میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ’’مجمع اللغۃ العربیۃ‘‘ کے تاحیات رکن رہے۔ اس سے قبل یہ اعزاز بھارتی عالم اورندوۃ العلماء کے سابق مہتمم سید ابوالحسن ندویؒ کے پاس رہا۔ امام کعبہ ۱۹۷۵ء میں پاکستان تشریف لائے تو ۲۵ سالہ ڈاکٹر غازی ان کے مترجم تھے ۔ امام کعبہ نے کہا کہ میری بات کو جتنی بہتر انداز میں محمود غازی بیان کر رہے ہیں، اتنا میں خود بھی نہیں کر پاتا۔ آپ نے اسی سال لیبیا میں ہونے والی عالمی سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔
ڈاکٹر غازی نے علامہ اقبالؒ کی شاعری کا عربی میں ترجمہ کیا اور ’’ پس چہ باید کرد،اے اقوام شرق‘‘ کے نام سے کتابیں لکھ کر فکر اقبالؒ کو عام فہم بنایا۔ آپ نے ۲۵ سے زائد کتابیں لکھیں۔ محاضرات قرآن، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت، محاضرات فقہ، محاضرات معیشت وتجارت سمیت کئی موضوعات پر خصوصی لیکچر دیے جو کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ آخری ایام میں وہ شیخ زاید اسلامک سنٹر جامعہ پشاو رکی دعوت پر ’’خطبات خیبر‘‘ کے نام سے لیکچرز دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انہیں عالمگیریت ، اسلامی معیشت وتجارت سمیت کئی موضوعات پر سنا۔ وہ گھنٹوں گفتگو کرتے اور سننے والے سنتے رہتے۔ اسلام آباد میں قائم مسلم تھنکرز فورم کے وہ مستقل خطیب اور سرپرست تھے اور ہمیشہ کلیدی خطاب انہی کا ہوتا تھا۔ وہ مختصر وقت میں گفتگو کا حق ادا کر دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ساجدالرحمن کے مطابق پاکستان میں عہد حاضر کی وہ غیر متنازعہ شخصیت تھی جوتمام مسالک و مکاتب فکر میں یکساں مقبول اور قابل احترام سمجھی جاتی تھی۔ ان کی وفات سے پاکستان کا نہیں، عالم اسلام کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے زندگی بھر کبھی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ صاحبزادہ ساجدالرحمن صاحب کہتے ہیں کہ وہ بگھار شریف کہوٹہ کئی مرتبہ آئے اور عرس کی تقریب سے خطاب بھی کیا۔ وہ مکتب دیوبند سے وابستہ تھے، لیکن تمام مکاتب فکر کا احترام کرتے اور اپنے تلامذہ کو بھی ادب واحترام کا درس دیتے۔ بھیرہ شریف کے جسٹس پیر کرم شاہ الازہریؒ کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے۔ پیر صاحب جب اسلام آباد آتے ، غازی صاحب سے ضرور ملتے۔ کئی مرتبہ غازی صاحب بھیرہ شریف گئے اور عرس کی تقریب سے خطاب بھی کیا۔ وہ اعتدال پسند انسان تھے ،ان میں جدت بھی تھی اور روایت پسندی بھی ۔ چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی، خوبصورت چشمہ، پینٹ کوٹ اورشرٹ سے ملتے رنگ کی نکٹائی، وہ وجیہ بھی تھے اور نفیس بھی۔ وہ صدی کے انسان تھے جنہیں صدیوں یاد رکھا جائے گا۔
ڈاکٹر غازی صاحب فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب رہے ، ادارہ تحقیقات اسلامی میں پروفیسر اور دعوہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ اپنے ادبی ذوق کی بنا پر کئی مجلوں کے ایڈیٹر بھی رہے۔ دنیا بھر میں کئی تحقیقی مجلات میں ان کے مضامین کو نمایاں طور پر شائع کیا جاتا ۔ اخبارات اورعلمی جرائد اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ڈاکٹر غازی نے ان کے لیے خصوصی طور پر کوئی مضمون لکھا ہے۔ وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر رہے، سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے جج رہے۔ جب صدر مشرف کی پہلی کابینہ میں انہیں اصرار کے ساتھ وفاقی وزارت مذہبی امور کا منصب سونپا گیا توان کے بھائی کا کہنا تھا کہ قوم آج ایک اچھے استاد سے محروم ہو گئی۔ صدر مشرف نے جب پاکستان میں ہوائی اڈے امریکی فوج کو دینے کی کوشش کی تو آپ نے اس فیصلے کی بھرپور مخالفت کی اور کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوگا جس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ وہ آمرانہ مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو سکے اور مشرف کی کابینہ سے مستعفی ہوگئے۔ وہ دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی کے خواہاں تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ نصاب وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں، اس لیے وہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے قیام کے لیے متحرک ہو گئے تاہم ان کی وزارت سے علیحدگی کے بعد ان کا یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر اور بعد میں چیئرمین بھی رہے۔ عہدے ان کے پیچھے دوڑتے رہے اور وہ علم وعمل کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وہ کئی بینکوں کے شرعی بینکاری بورڈ کے ڈائریکٹر اور ایڈوائزر بھی رہے۔
۲۶؍ ستمبر کی شب ۱۱ بجے انہیں دل کی تکلیف ہوئی تو انہیں پمز ہسپتال لے جایا گیا۔ نماز فجر کے وقت جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ زندگی کا آخری سجدہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ خدا کے حضور دارز کیے۔ آٹھ بج رہے تھے کہ انہوں نے پاکیزہ لبوں پر کلمہ شہادت سجایا، نم آنکھوں کے ساتھ خدا کے حضور جبین جھکائی اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد اپنی جان، جان کے خالق کے ہاتھ میں دے دی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ انہوں نے اپنے پسماندگان میں ۵ بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑی۔ اللہ ان کے خاندان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔آمین۔
صدر آصف علی زرداری ، وزیر اعظم سید یوسف گیلانی ، اسپیکر ، ڈپٹی اسپیکر، آرمی چیف سب نے ان کے انتقال پر گہرے رنج وغم کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ، اور وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس آغا رفیق نے ڈاکٹر غازی کی وفات کوعلمی، ادبی، فکری اور تحقیقی حلقوں کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے ان کی روح اور درجات کی بلندی کے لیے ان کے گھر آکر دعا کی۔
ڈاکٹر غازی کی نماز جنازہ میں ملک بھر سے مختلف مسالک کے جید علماء کرام، صاحبان علم ودانش، صوفیا، علما، طلبہ وطالبات ، پارلیمان کے اراکین ،سرکاری عمال الغرض سبھی شریک تھے۔ مسلم لیگ (ن) کے راجہ ظفر الحق ، سینیٹر پروفیسر خورشید احمد، سینیٹر محمدخان شیرانی سمیت سابق اراکین پارلیمنٹ ، سپریم کورٹ ، ہائی کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں ،اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران، کئی ممالک کے طلبہ اور علما، مصر اور سعودی سفارت خانے کے اہل کاروں کے علاوہ دینی رہنماؤں اور کئی جامعات کے وائس چانسلرز نے بھی ان کے جنازہ ، تدفین اور دعا میں شرکت کی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر، ڈاکٹرانوار حسین صدیقی نے شدید علالت کے باوجود جنازے اور تدفین کے عمل میں شرکت کی۔ ڈاکٹر ذاکر اے نائیک، مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، سید عدنان کاکاخیل، مولانا محمد زاہد، مفتی محمد نعیم، مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، مولانا محمد احمد لدھیانوی، ڈاکٹر خادم حسین ڈھلوں، ڈاکٹر ایس ایم زمان، سجاد افضل چیمہ، میاں نواز شریف، احسن اقبال، جسٹس فدا محمد، صدیق الفاروق سمیت دنیا بھر کے کئی اہم شخصیات نے ان کی وفات پر گہرے رنج وغم کا اظہار کیا اورانہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلم ہینڈز پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر سید ضیاء النور شاہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر غازی کے وجود سے انسانیت کی خوشبو آتی تھی۔ ہر طرف سے نفرت وتعصب کی آوازیں بلند ہوتی تھی، لیکن ڈاکٹر غازی نے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب نے کہاکہ ان کی و جہ سے لوگ جڑے ہوئے تھے اور نفرتوں کی دیواریں بلند نہیں ہوپاتی تھی۔ ڈاکٹر غازی کے انتقال سے عالم اسلام ایک جلیل القدر علمی اور تحقیقی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کے علمی کمال کی خوشبو انسانوں کے ذہنوں اور دماغوں کو معطر ومنور رکھے گی۔ ان کی قبر پر کھڑے اچانک میں نے سامنے دیکھا تو مجھے فیصل مسجد نظر آئی اور دائیں طرف دیکھا تو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی عمارت تھی۔ یہ وہ مقامات ہیں جنہیں ڈاکٹر غازی نے اپنے خون پسینے کی محنت سے سینچا تھا اور آج یہ گلشن مہک رہے ہیں۔
(بشکریہ ’’قیام‘‘ اسلام آباد، نومبر / دسمبر)
تواریخ وفات ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ
مولانا ڈاکٹر خلیل احمد تھانوی
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ میرے پھوپھی زاد بھائی مولانا محمداحمد صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے۔ علوم دینیہ اور علوم دنیویہ دونوں کے ماہر تھے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت تھے۔ انہوں نے پاکستان میں اسلامی قوانین کی ترتیب وتدوین میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اسلام آباد یونیورسٹی میں عرصہ دراز تک اپنے علوم سے طلبہ کو مستفید فرماتے رہے۔ میں نے محترم ڈاکٹر صاحب کی تواریخ وفات کچھ مفید جملوں اور کچھ آیات قرآنی سے مرتب کی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا آئینہ دار ہونے کے ساتھ ان کے سن وفات کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔
قرآنی آیات سے نکالی گئی تواریخ کو اگر ترتیب سے پڑھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے لیے نیک فال بھی ہیں۔ پہلی آیت میں ان کے لیے بشارت ہے کہ اس دارفانی سے اپنے رب کی طرف چلو اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی ۔ دوسری آیت میں ان کے پس ماندگان کے لیے صبر کی تلقین ہے کہ ان کی جدائی سے پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کی معیت عطا فرمائی ہے جن پر اللہ کاانعام ہوا ہے۔ تیسری آیت میں بشارت ہے کہ ان کے صبر کا بدلہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اور چوتھی آیت میں یہ خوشخبری ہے کہ اے متعلقین، تم صبر کر واور خوش ہو جاؤ کہ وہ بہت ہی پرعیش زندگی میں ہیں۔
اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب پس ماندگان کو صبر جمیل عطافرمائے اور ڈاکٹر صاحب کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ تعزیتی پیغامات و تاثرات
ادارہ
( ۱ )
محترم جناب مدیر صاحب ، ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی سے طویل محبت کا تعلق رہا ہے۔ ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں ا کٹھے کام کرتے رہے ہیں۔ اور بھی بہت سے قومی، ملی، مقامی اور عالمی کاموں میں مشاورت رہی۔ حال ہی میں ان کی اچانک وفات سے تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل یعنی شعبان ۱۴۳۱ھ کے آخری عشرے میں مکہ مکرمہ میں رابطۃ العالم الاسلامی کی جو تین روزہ کانفرنس ہوئی، اس میں بھی ان کے ساتھ مفید اور پرلطف رفاقت رہی۔ میرا ان سے قلبی تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ دل چاہتا ہے کہ ان کے متعلق کچھ ضرور لکھوں، لیکن عوارض اور ہجوم مشاغل کے باعث اس سعادت میں شریک نہ ہو سکوں گا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ’’ الشریعہ ‘‘ کے نمبر کو جوآپ مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے بارے میں شائع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مکمل کامیابی سے نوازے۔
محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ
رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی
( ۲ )
جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ جن کا انتقال چندماہ قبل ہوا، پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت اور ملت اسلامیہ کا نہایت بیش قیمت سرمایہ تھے۔ ان کی وفات صر ف اہل پاکستان ہی کے لیے نہیں، پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا المیہ اور بظاہر ناقابل تلافی نقصان ہے۔
ڈاکٹر صاحب موصوف اپنی خصوصیات وامتیازات کی وجہ سے ایک منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ دینی و دنیوی تعلیم کا حسین امتزاج اور قدیم و جدید علوم و نظریات میں ماہرانہ شناسائی میں ممتاز تھے۔ وہ ایسے دینی وعلمی خانوادے کے چشم وچراغ تھے جو دیوبند سے قرب مکانی کا شرف بھی رکھتا تھا اور نظریاتی اعتبار سے بھی مسلک دیوبند ہی پر کاربند تھا، لیکن مرحوم کا امتیاز یہ رہا کہ وہ نہ صرف خود فقہی جمود اور مسلکی تعصب سے بہت حد تک دور رہے بلکہ اس جمود اور تعصب کو کم کرنے میں عمر بھر کوشاں رہے۔
اسلام آباد میں منعقدہ علمی سیمیناروں اور کانفرنسوں میں جب بھی ان کو موقع ملتا، اور اکثرا ن کو ایسے مواقع ملتے رہتے تھے، وہ مسلکی ونظریاتی وابستگی سے بالا ہو کر ملت کی وحدت ویگانگت کے نقطہ نظر سے فقہی جمود کے خلاف آواز ضرور بلند کرتے۔ وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، حتیٰ کہ مشرف دور میں وزیر مذہبی امور بھی رہے، لیکن انکسار اور عاجزی ان کے مزاج کا جزو لاینفک رہی۔ بلند پایہ اہل علم وقلم ہونے کے باوجود دوسرے اہل علم وقلم کا احترام اوران کی علمی خدمات کی تعریف کرتے۔ راقم کی کتاب ’’خلافت وملوکیت کی تاریخی وشرعی حیثیت‘‘ جو مولانا مودودی مرحوم کی ’’خلافت وملوکیت‘‘ کے جواب میں لکھی گئی تھی، ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند تھی اور راقم سے جب بھی ملاقات ہوتی تو وہ یہ فرمائش ضرور کرتے کہ اس کی تلخیص کر دیں تاکہ اس کادائرۂ افادیت مزید وسیع ہو جائے۔
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ذیلی ادارہ دعوہ اکیڈمی کے وہ ڈائریکٹر اورروح رواں تھے او را س کے زیر اہتمام انہوں نے اسلامی موضوعات پر حالات حاضرہ کی روشنی میں نہایت مفید لٹریچر تیار بھی کروایا اور شائع بھی کیا۔ یہ مطبوعات وقت کی نہایت اہم ضرورت ہیں جویقیناًان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے، ان شاء اللہ۔ خود ان کی تالیفات بھی جوزیادہ تر تقاریر اور محاضرات پر م مبنی ہیں، بغایت مفید اور متجددین کے شکوک وشبہات کے ازالے کے لیے نہایت موثر اور مسکت ہیں۔ یہ بھی ان کا صدقہ جاریہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے وہ ہر حلقے میں ہر دلعزیزبھی تھے اور اسلام کا ایک بہترین نمائندہ بھی۔ان کا خلا ایک مدت تک نہایت شدت سے محسوس کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت کی برکات سے ان کو سیراب فرمائے۔ غفراللہ ورحمہ وجعل الجنۃ مثواہ۔
حافظ صلاح الدین یوسف
(مدیر شعبہ تحقیق وتالیف دارالسلام ،لاہور)
( ۳ )
مکرمی مولانا ناصر صاحب حفظہ اللہ
سلام مسنون
آپ کا دوسرا مکتوب گرامی ملا۔شکریہ! آپ کا پہلا نواز ش ]نامہ[ نہیں ملا۔ ادھر تقریباً دو سال سے خاکسار کا ادارۂ ثقافت اسلامیہ سے تعلق نہیں رہا۔شاید اس لیے وہ مجھے نہیں ملا۔ آپ کا رسالہ ’الشریعہ‘ ایک مدت تک میری نظر سے گزرتا رہا۔ مسائل حاضرہ کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھنے پر آپ کو مبارک باد دیتا ہوں۔ ہم نے ’الشریعہ‘ کا ایک مقالہ ’المعارف‘ میں بھی نقل کیا تھا۔
آپ مرحوم ڈاکٹر غازی پر ’الشریعہ‘ کا خاص نمبر نکال رہے ہیں۔ اس پر میں مبارک باد دیتا ہوں۔ جب میں ادارۂ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد گیا، اس وقت جواں سال غازی مرحوم ادارہ میں تھے۔ ان سے جب کبھی ملنا ہوا، انھیں ایک سنجیدہ نوجوان پایا۔ ادارہ سے نکلا اور متعدد مقامات میں رہا۔ جب کبھی اسلام آباد جانا ہوا، ان سے ملتا رہا، ہرچند ان کا تعلق ایک سیاسی مذہبی جماعت سے تھا جو متعدد اسلامی دانش مندوں کو جو اپنے موضوع پر عبور رکھتے ہیں، سیکولر اور غیر سیکولر کے پیمانوں سے ناپتی تھی اور ان کے سامنے ضیاء الحق اور ان جیسے جابر حاکموں سے مل کر زہر کا پیالہ پیش کرتی تھی۔ خود اس خاکسار کو ضیاء الحق کے ہاتھوں اس پیالے کو دو دفعہ پینا پڑا۔ ان دنوں میں اتفاق سے مرحوم ڈاکٹر غازی سے ملنا ہوا تو انھیں افسردہ پایا۔ وہ اختلاف رائے کی بنا پر دوسروں کے منہ سے نوالہ چھیننے کے قائل نہیں تھے۔
غرضیکہ اس قسم کے واقعات کی بنا پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ ایک شریف انسان تھے جو اختلاف رائے کی بنا پر اپنے ہم عصر اہل علم کے درپے آزار ہونے (suppression) کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے میری رائے تھی کہ انھیں ایک ’’مذہبی سیاسی‘‘ جماعت کی طرف منسوب کرنا صحیح نہ ہوگا۔ البتہ میری اخلاص سے یہ رائے ہے کہ اگر وہ ظفر احمد انصاری اور افضل چیمہ سے دور رہتے تو وہ علمی میدان میں ٹھوس اور مثبت روایت قائم کر سکتے تھے۔ البتہ مرحوم ابوالحسن سید علی ندوی ایک نیک، مخلص اہل علم تھے۔ ان سے ڈاکٹر غازی کی عقیدت اور ملاقاتیں ان کے لیے یقیناًسود مند رہیں، کیونکہ مرحوم غازی صاحب بنیادی طور پر علمی اور اخلاقی آدمی تھے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ انھیں اپنی رحمت سے نوازے۔ آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مرحوم ڈاکٹر غازی کا تذکرہ چھیڑا اور مجھے ’’یاد ماضی عذاب ہے ساقی‘‘ کے حوالہ کر دیا۔
کبھی لاہور آنا ہو تو آپ سے مل کر مسرت ہوگی۔
(ڈاکٹر) رشید احمد (جالندھری)
( ۴ )
کل من علیہا فان، و یبقٰی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام (الرحمن ۵۵: ۲۶۔ ۲۷) ہر چیز جو اس زمین پر ہے، فنا ہوجانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل وکریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔
قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جو صداقت بیان کی گئی ہے، بار بار مطالعہ کے باوجود ہم اسے اکثر بھول جاتے ہیں لیکن بعض حادثات ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور اس وقت اس آیت کا مفہوم ذہن میں تازہ ہو تا ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے ،فنا ہو جانے والی ہے اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہنے والی ہے۔
کل تک یہ بات وہم وگمان میں بھی نہ تھی کہ آج ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمارے ساتھ نہ ہوں گے۔ میں کراچی میں تھا جب ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کے انتقال کی خبر ملی ۔ یہ خبر میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ ابھی چند ہفتے قبل ہم نے رابطۃ العالم الاسلامی کے پچاسویں یوم تاسیس کی تقریب میں مکہ مکرمہ میں شرکت کی، ایک ساتھ جہاز میں سفر کیا اور حرم شریف میں نمازوں میں شرکت کی تھی۔ مکہ مکرمہ جاتے وقت میں اور میری اہلیہ جہاز میں بیٹھے تھے کہ غازی صاحب جہاز میں داخل ہوئے اورمجھے دیکھ کر انتہائی گرم جوشی کے ساتھ جھک کر میری پیشانی پر بوسہ دیااور پھریہ کہا: میں قطر میں تھا تو ڈاکٹر منذر قحف صاحب نے بااصرار کہا تھا کہ جب آپ ڈاکٹر انیس سے ملیں تومیری طرف سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیں۔ اللہ اکبر! کل کی بات ہے اور آج ہم ایک ایسے صاحب علم سے محروم ہو گئے جونہ صرف اپنے علم وتقویٰ بلکہ برادرانہ تعلق کی بنا پر ہمارے گھر کا ایک فرد تھا۔
۱۹۸۰ء میں جب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے تصور سے نکل کر ایک قابل محسوس شکل اختیارکی تو ادارہ تحقیقات اسلامی کو، جو اس سے قبل مختلف سرپرستیوں میں رہا تھا، یونی ورسٹی کا حصہ بنا دیاگیا اور مرحوم ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتاصاحب، جو ادارے کے سربراہ تھے اور ڈاکٹر محمود احمد غازی جو ادارے میں ریڈر تھے، مع دیگر محققین کے یونی ورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں شاید ہی کوئی دن ایساہو جب ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اکثر حسین حامد حسان صاحب جو اس وقت کلیہ شریعہ کے ڈین تھے اور بعدمیں یونیورسٹی کے صدربنے، سرشام ہی مجھے، ڈاکٹر حسن محمود الشافعی اور اکثر ڈاکٹرمحمود احمدغازی کو ا پنے گھربلا لیتے اور رات گئے یونی ورسٹی کے بہت سے مسائل پر ہم سب مصروف مشور ہ رہتے۔ دعوہ اکیڈمی کاقیام ۱۹۸۳ء میں عمل میںآیا اور مجھے اس کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن افرادنے ہر مرحلہ میں میرے ساتھ تعاون کیا، ان میں ڈاکٹر حسن شافعی اور محمود غازی پیش پیش تھے۔ بعض وجوہ کی بنا پر میں دعوہ اکیڈمی سے الگ ہوا تو ڈاکٹر غازی نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور جب میں دوبارہ اکیڈمی کا ڈائریکٹر جنرل بنا تو وہ اکثر یہ کہتے کہ میں آپ کاخلیفہ ہوں اور آپ میرے خلیفہ ہیں۔
ڈاکٹر غازی کی یاد داشت غضب کی تھی اور برس ہا برس گزرنے کے بعد بھی واقعات کی ترتیب وتفصیل بیان کرنے میں انہیں یدطولیٰ حاصل تھا۔ ڈاکٹر صاحب اثر انگیز خطیب اور پر فکر تحریر کی بنا پر اس دور کے چند معروف اصحاب قلم میں سے تھے۔ ان کے قرآن کریم، حدیث، سیرت پاک، فقہ، شریعت، اور معیشت وتجارت کے موضوع پر خطابات کتابی شکل میں طبع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر کتب میں قانون بین المالک، اسلام اور مغرب تعلقات، مسلمانوں کا دینی وعصری نظام تعلیم، اسلامی بنک کاری: ایک تعارف ، ادب القاضی، اور قرآن مجید: ایک تعارف شامل ہیں۔ وہ ایک دردمند دل رکھنے والے محقق، عالم ،مفکر اور فقیہ تھے۔
پاکستان میں سودی بنکاری سے نجات کے لیے جن لوگوں نے کام کیا اور خصوصاً جب معاملہ سپریم کورٹ کے اپیلٹ بنچ میں گیا اور پھر سپریم کورٹ کے فل بنچ نے اس مسئلے کا جائزہ لیا تو اس میں غازی صاحب نے نمایاں کردار ادا کیا۔ فیڈرل شریعہ کورٹ میں جس طرح ڈاکٹر فداء الرحمن صاحب نے فیصلے کی تحریر میں کردار دا کیا، ایسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس خلیل الرحمن صاحب اور ڈاکٹر غازی کا اہم کردار رہا۔ ۸۰ء کے عشرے میں جنوبی افریقہ میں قادیانیوں کے حوالے سے عدالتی کارروائی میں پاکستان کے جن اصحاب علم نے عدالت عالیہ کو اس مسئلے پر رہنمائی فراہم کی، ان میں مولانا ظفر احمد انصاری، پروفیسر خورشید احمد صاحب، جسٹس افضل چیمہ صاحب مرحوم اور ڈاکٹر غازی کے نام قابل ذکر ہیں۔ دعوہ اکیڈمی کے ساتھ میرے طویل تعلق میں شاید ہی کوئی پروگرام ایسا ہو جن میں ملک کے اندر یا ملک سے باہر کوئی تربیتی کورس ہو ا اور اس میں ڈاکٹر غازی نے شرکت نہ کی ہو۔
ڈاکٹر غازی کو اردو، عربی، انگریزی میں خطاب کرنے میں عبور حاصل تھا۔ وہ فرانسیسی زبان بھی جانتے تھے۔ ڈاکٹر غازی نے صدر جنرل پرویز مشرف کی کابینہ میں مذہبی امور کے وزیر کے فرائض بھی انجام دیے اور بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی کے صدر اور نائب صدر کے علاوہ یونیورسٹی کی شریعہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ ان کی علمی خدمات کی بناپر انہیں ملک میں اور ملک سے باہر ایک معروف اسکالر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔
ڈاکٹر غازی ایک حلیم الطبع انسان تھے۔ اکثر اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمدا لغزالی کی چھیڑ چھاڑ سے خود بھی محظوظ ہوتے اور کبھی اپنے بڑے ہونے کے حق کواستعمال نہ کرتے۔ نجی محفلوں میں ان کی حاضر جوابی اور ذہانت ہمیشہ انہیں دیگر حاضرین سے ممتاز کرتی۔ مہمانوں کی تواضع میں ہمیشہ پیش پیش رہتے۔ ان کی وفات نے جو خلا پاکستان بلکہ عالم اسلامی کی علمی صفوں میں پیدا کیا ہے، وہ عرصے تک ان کی یاد کو تازہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کریم سے تعلق اور دین کی اشاعت کے لیے خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔
ڈاکٹر انیس احمد
(ماہنامہ ترجمان القرآن، نومبر ۲۰۱۰ء)
( ۵ )
راقم الحروف دوران تعلیم شدید بیمار ہو گیا اور تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔صحت یابی کے بعد جب ۱۹۶۸ء میں دار العلوم تعلیم القرآن، راجہ بازار، راول پنڈی میں دورۂ حدیث شریف میں داخلہ لیا تو محمود غازی نام کا ۱۴، ۱۵ سالہ نوخیز لڑکا بھی ہمارے ساتھ شریک دورہ تھا جو دیگر طلبہ سے بہت کم عمر تھا۔ زبان میں قدرے لکنت تھی، مگر ذہانت اور حافظہ کے اعتبار سے تمام طلبہ پر فوقیت حاصل تھی۔ عبارت پڑھنے میں کہنہ مشق استاذ کی طرح ماہر تھا۔ ترجمہ اور تشریح میں بھی خاصی دسترس حاصل تھی۔ سالانہ امتحان میں نمایاں کامیابی سے ہم کنار ہوا۔
محمود غازی قابل رشک فہم وذکا اور عدیم النظیر قابلیت کے پیش نظر اساتذہ کے منظور نظر اور طلبہ کے ہر دل عزیز ساتھی تھے۔ شرافت ومتانت ان کی ہر ادا سے ہویدا تھی۔ عموماً لائق طلبہ بہت شریر ہوتے ہیں۔ اگر اور کچھ نہ بن پڑے تو اساتذہ کو لایعنی سوالات میں الجھائے رکھتے ہیں، لیکن غازی سے اساتذہ نہ صرف خوش تھے بلکہ ان کی تعریف وتوصیف کے خوگر بھی تھے۔
محمود احمد غازی کے لیے، جو ۱۷، ۱۸ سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فارغ ہو گئے، یہ بات یقیناًطرۂ امتیاز ہے کہ انھوں نے صغر سنی میں علوم عقلیہ ونقلیہ سے فراغت حاصل کر کے بعض اکابر کی یاد تازہ کر دی۔ بعد ازاں متعدد یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیمی اسناد اور ڈگریاں حاصل کیں۔ ڈاکٹر غازی کی زندگی کا بیشتر حصہ ایسے ماحول میں بسر ہوا جہاں دینی شعائر کا تحفظ اور تقدس ثانوی حیثیت رکھتا ہے، مگر ڈاکٹر غازی نے اسلامی علوم کی لاج رکھی اور علما ومشائخ سے اپنا تعلق مضبوط اور قائم رکھا جس کا شاہکار ثبوت ان کی نادرۂ روزگار تصانیف ہیں جن میں اسلامی روح اور اسپرٹ نمایاں ہے اور اکابر محققین وعلما نے ان تصانیف کو توصیف وتحسین سے نوازا ہے۔
اللہ رب العزت نے ڈاکٹر غازی کو حکومت کے اعلیٰ مناصب پر بھی فائز اور متمکن فرمایا، لیکن ان کی طبیعت اور مزاج میں سرمو فرق نہیں آیا۔ ان کے دل میں دین دار طبقہ اور دینی شعائر کی عظمت موج زن رہی۔جناب ڈاکٹر صاحب کو تبلیغی جماعت سے قلبی وابستگی تھی۔ اسلام آباد کے سالانہ اجتماعات میں عام سامعین کے ساتھ شریک ہونا اور بغیر کسی کروفر کے فرش خاکی پر جلوہ افروز ہونا معمول تھا۔ احقر نے بچشم خود ڈاکٹر غازی کو گھاس پر بڑی طمانیت اور وقار سے بیٹھ کر اکابر کے بیانات سنتے دیکھا ہے۔ علماء کرام اور مشائخ عظام کی قدر ومنزلت اور عزت وتکریم ان کا شیوہ تھا۔ علماء کرام کی دعوت وطلب پر مدارس کے اجتماعات میں شریک ہونا اپنے لیے سعادت تصور کرتے تھے۔ بلاوجہ عذر ومعذرت سے کبھی کام نہیں لیا اور بڑے ذوق سے اکابر کی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازتے تھے۔
اللہ رب العزت نے انھیں وفاقی وزیر مذہبی امور کے منصب سے نوازا تو بحمد اللہ حج کے انتظامات نہایت احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ حجاج کرام کو ہر ممکن سہولیات اور طمانیت اور دل جمعی کے ساتھ مناسک حج ادا کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ وزارت کے پورے عرصے میں مدینۃ الحجاج اسلام آباد میں حجاج کرام کی تربیت کا خصوصی انتظام ڈاکٹر غازی صاحب کی سربراہی میں قائم رہا۔ حجاج کرام کو مسائل حج سے پوری طرح روشناس اور آگاہ کرنے کا بہترین نظم تھا اور خود بھی حجاج کرام کی راہنمائی کے لیے خطاب کیا کرتے تھے۔
جن دنوں ڈاکٹر محمود غازی وزیر مذہبی امور تھے، وزارت حج کے دفتر سے راقم الحروف کو فون آیا کہ آپ اپنا پاسپورٹ فوری طو رپر دفتر میں جمع کرائیں، پرسوں حج کے لیے آپ کی فلائٹ ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری درخواست کے بغیر حج کی منظوری کیسے ہو گئی! آخر غازی صاحب کے متعلق خیال ہوا کہ انھوں نے اپنی پرانی دوستی کا حق ادا کیا ہے اور نظر عنایت فرمائی ہے۔ جو کام خلوص وللہیت سے، محض رب کی رضا کے لیے ہو، اس کے اظہار وافشا سے اللہ کے نیک بندے گریز ہی کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جہاز کا دو طرفہ ٹکٹ احقر نے خرید لیا، رہائش اور ٹرانسپورٹ وزارت مذہبی امور نے فراہم کر دی۔ مکہ مکرمہ میں جناب غازی صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے شکریہ ادا کیا، لیکن انھوں نے قطعاً نہ تو احسان جتلایا اور نہ ہی فخر وتکبر کی کوئی بات کی، بلکہ بالکل خاموش رہے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی کی معرکۃ الآرا تصنیف ’’ادب القاضی‘‘ جب منصہ شہود پر آئی تو انھوں نے اس کے لیے عالی شان تقریب کا اہتمام کیا۔ ادارۂ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے ایک وسیع وعریض ہال میں نقاب کشائی کا پروگرام رکھا جس میں سرکاری سطح کے افسران مدعو تھے۔ غازی صاحب نے احقر کو بھی دعوت شمولیت دی اور کتاب لاجواب کا ہدیہ بھی مرحمت فرمایا۔ موصوف کی جملہ تصانیف انتہائی قابل قدر اورلائق صد تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے اور اخری منازل آسان فرمائے۔
(مولانا) محمد عبد المعبود
باغ سرداراں، راول پنڈی
( ۶ )
مخدومی ومحترمی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم۔ مزاج گرامی!
جنوبی افریقہ کیس کے لیے مختلف وفود گئے۔ پہلا وفد ستمبر ۱۹۸۲ میں گیا۔ اس میں جناب مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا مفتی زین العابدین، جناب غیاث محمد، جناب گیلانی، مولانا عبد الرحیم اشعر ودیگر حضرات شامل تھے۔ ان میں حضرت ڈاکٹر محمود احمد غازی شامل نہ تھے۔ دوسرا وفد نومبر ۱۹۸۴ء میں گیا۔ اس میں حضرت غازی صاحب شریک تھے۔ جن حضرات کا عدالت میں بیان ہونا طے ہوا، ان میں محترم حضرت غازی صاحب کا نام بھی تھا۔ بیان ہوا؟ کب؟ کیا؟ تلاش سے مل سکے تو انعام الٰہی ہوگا، ورنہ اس تنخواہ پر گزارہ کیے بغیر چارہ نہیں۔
ایک بار سرکاری سطح پر ’’قادیانیت: اسلام کے خلاف سنگین خطرہ‘‘ کے نام سے حکومت پاکستان نے ایک وقیع مقالہ شائع کیا۔ جن دنوں وفاقی شرعی عدالت میں جنرل محمد ضیاء الحق کا جاری کردہ امتناع قادیانیت آرڈیننس زیر سماعت تھا، ایک مجلس میں فقیر نے ایک حوالے کے سلسلے میں متذکرہ رسالہ کا نام لیا۔ اس پر غازی صاحب نے تعجب کے ساتھ فقیر کی طرف دیکھا۔ فقیر نے بعد میں تعجب کے ساتھ نظر کرم کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ وہ رسالہ میرا مرتب کردہ ہے۔ (غالباً ان دنوں وزارت مذہبی کے آپ سربراہ تھے)۔ وہ رسالہ مل گیا، اس کا فوٹو بھی ارسال خدمت ہے۔ یہ رسالہ غازی صاحب کا مرتب کردہ ہے۔
جن دو قسطوں میں مولانا منظور احمد الحسینیؒ نے جنوبی افریقہ کیس کے حوالے سے محترم غازی صاحب کا ذکر خیر فرمایا ہے، ان کا فوٹو لف ہے۔ معافی چاہتا ہوں کہ تعمیل ارشا د میں تاخیر ہوئی۔ اس کا باعث یہ تھا کہ فقیر دفتر سے غیر حاضر تھا۔
(مولانا) اللہ وسایا
مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان
( ۷ )
ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کاتذکرہ کرتے ہوئے مجھے ڈاکٹر شیر محمد زمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنھوں نے غائبانہ تعارف کروایا۔غازی صاحب اس وقت دعوہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل تھے ۔ڈاکٹر زمان صاحب زید مجدہم کے تعارف سمیت ان سے ملا قات ہوئی۔تجویز یہ تھی کہ میں ان کی اکیڈمی سے وابستہ ہو جاؤں۔ راقم کے لیے یہ بہت اہم بات تھی، اس لیے کہ وہ بے روزگاری کا زمانہ تھا۔ راقم کے مضمون کی مناسبت سے غازی صاحب نے کہا کہ ہم اردو کا ایک رسالہ نکالیں گے جس کی ادارت آپ کے سپرد کی جائے گی، چنانچہ انھوں نے اس رسالے کی تجویز بنا کر بھیجی جو منزلوں پر منزلیں مارتی رہی۔ یونی ورسٹی کے صدر صاحب مصر میں تھے اور تجویز پاکستان میں۔ اگرچہ وہ پاکستان آتے رہتے تھے، لیکن کئی برس کے تعاقب کے بعد تجویز ان تک پہنچی، مگر اس لیے نامراد لوٹ آئی کہ یہ عربی میں تیار نہیں کی گئی تھی۔ اردو رسالے کے لیے انگریزی میں تیار کی گئی تجویز نے عربی لباس پہنا اور بالآخر منظور ہوگئی، لیکن اس وقت تک راقم کی زندگی کئی منزلیں طے کرچکی تھی۔ بے روزگاری کا زمانہ قصہ ماضی بن چکا تھا۔ رسالے کے اجرا سے پہلے غازی صاحب کا پیغام آیا کہ آپ کے لیے جو تجویز بھیجی گئی تھی، وہ منظور ہوگئی ہے، لیکن راقم ا پنی موجود منزل سے غیر مطمئن نہیں تھا، اس لیے معذرت ہی کو مناسب سمجھا گیا چنانچہ رسالہ تو نکل آیا، لیکن اس کی ادارت کی ذمہ داری کسی اور نے اٹھائی۔ اقبال:
پرید ن از سر بامے بہ بامے
نہ بخشد جرہ بازاں را مقامے
اس کے کئی برس بعد غالباً ۲۰۰۳ء میں انھوں نے ایک پر محبت خط لکھ کر ایک بار پھریہ خواہش کی کہ میں ان کی یونی ورسٹی سے وابستہ ہو جاؤں۔ اس وقت مجھے اپنی مادر علمی پنجاب یونی ورسٹی سے وابستہ ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا، چنانچہ اب بھی ان کی خواہش پوری نہ کرسکا، تاہم ان کے ساتھ باہمی احترام اور اخلاص کا تعلق رہا۔ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ پہلی بار انھیں تین مختلف ٹیلی فونوں پر باری باری عربی، انگریزی اور اردو میں یکساں مہارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر جو خوش گوار حیرت ہوئی تھی، وہ قائم رہی اور ان کی علمیت کا نقش گہرا ہوتا چلا گیا۔ ان کے ساتھ شخصی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کے علم و فضل اور اعتماد سے بھرپورلیکچر سننے کا بھی موقع ملا۔ لیکچر کے دوران ان کا یہ طریقہ دیکھا کہ وہ چھوٹے سائز کے بہت سے کارڈوں پر لکچر کے نکات لکھ کر لاتے تھے اوردوران لکچر یہ کارڈ ان کے ہاتھ میں رہتے۔ جو جو نکتہ بیان ہوتا رہتا، اس سے متعلق کارڈ، کارڈوں کی تہہ کے نیچے جاتا رہتا۔ کسی ایک کاغذ پر نکات لکھ کر لانے کے مقابلے میں یہ طریقہ زیادہ جدید لگا۔
راقم جب پنجاب یونی ورسٹی کی سیرت کمیٹی کا سیکریٹری تھا تو اس کے ایک اجلاس سے خطاب کے لیے غازی صاحب کو بھی دعوت دی گئی۔ اس زمانے میں وہ مذہبی امور کے وفاقی وزیر تھے۔ جس سادگی اور بے غرضی کے ساتھ وہ اس اجلاس کے لیے اسلام آباد سے تشریف لائے، اس نے میرے دل میں ان کی وقعت میں اضافہ کیا۔ وزارت کے بعد بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی اسلام آباد کے نیو کمپس میں ان کے دفتر میں ہوئی تھی۔ وزارت کا کوئی رنگ باقی نہ تھا۔ ان کا کمرہ ایک پروفیسر کاکمرہ تھا۔ یہاں سے ہم اکٹھے فیصل مسجد گئے۔ راستے میں ہماری ایک مشترک محترم، صاحب علم شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ غازی صاحب کہہ رہے تھے، اہل علم کوچاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حکومتوں سے وابستہ نہ کریں۔ شاید یہ رائے انھوں نے اپنے تجربے کے بعد قائم کی تھی۔
یہاں مصر میں جس محفل میں بھی ان کا ذکر ہوا، اہل مصر کو ان کی صلاحیتوں کا مداح اور معترف پایا۔ دنیا کی دوسری بڑی جامعات کی طرح جامعہ الازہر میں بھی پی ایچ ڈی کے مقالات کو جانچ کے لیے بیرونی ممالک کے ممتحنین کے پاس بھیجنے کا طریقہ رائج ہے۔ اساتذہ کی ترقی کے لیے بھی ان کے کام کو رائے کے لیے بیرونی دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ پی ایچ ڈی جس مضمون میں بھی ہو، عام طور سے مقالہ عربی میں لکھا جاتا ہے۔ یہی صورت اردو میں پی ایچ ڈی کی بھی ہے، چنانچہ ایسے غیر ملکی ممتحنین کی ضرورت رہتی ہے جو متعلقہ مضمون کے ساتھ عربی پر بھی اچھی دسترس رکھتے ہوں۔ اب اردو میں تو ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو عربی زبان میں کی گئی اردوتحقیق کو جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایک ایسی ہی میٹنگ میں غازی صاحب کا نام تجویز کیاگیا۔ راقم نے بتایا کہ وہ آج کل پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے جج ہیں۔ اس پران کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے ہماری فیکلٹی کے ڈین صاحب نے کہا کہ وہ تو اس سے بھی بڑے منصب کے اہل ہیں۔ ایک صاحب علم کا کہنا تھا کہ ان کی عربی کے سامنے تو ہم خود کو شرمندہ شرمندہ محسوس کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جاپان کی دوشیشہ یونی ورسٹی نے اسلامیات کے موضوع پر مشارکت کے لیے پاکستانی اہل علم کی بابت دریافت کیا تو راقم نے غازی صاحب کا نام تجویز کیا۔ اس پر معلوم ہوا کہ وہاں بھی ان کے مداح موجود ہیں، لیکن قبل اس سے کہ وہ دوشیشہ یونی ورسٹی کی دعوت پر جاپان جاتے، ابدالآباد سے ان کا بلاوا آگیا۔ مولانا روم:
پس عدم گردد عدم چون ارغنون
گو ید م کانّا الیہ راجعون
ڈاکٹر زاہد منیرعامر
(وزیٹنگ پروفیسر مسند اردو ومطالعہ پاکستان،
جامعہ الازہر قاہرہ۔مصر)
( ۸ )
فکری تنگ دستی، نظریاتی بے گانگی بلکہ نظریاتی انحراف کے اس عہد میں ایسے دانشور، محقق اور افراد نایاب ہیں جو نہ صرف کسی نظریے یا فکر کے پیرو کار یا علمبردار ہوں بلکہ خود اس کا ایک مثالی نمونہ بھی ہوں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم ایک ایسے ہی استاد و محقق تھے جن کی ذات ان کے نظریات کی آئینہ دار تھی۔ بلا شبہ وہ عصر حاضر میں ملت اسلامیہ کے ایک ایسے قابل فخر فرزند تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو ان کی حقیقی روح کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا ۔ وہ فکری انتہا پسندی کے حامی نہ تھے۔ نام نہاد روشن خیالوں یا راسخ العقیدگی کے دعوے داروں نے باہمی آویزش سے دنیا میں جو اندھیرا مسلط کر رکھا ہے، اس میں ڈاکٹر محمود احمد غازی ان معدودے چند افراد میں نمایاں تھے جنہوں نے توازن فکر کا چراغ روشن کیا، جو مسلمانان عالم کے اتحاد کے داعی تھے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی اردو، انگریزی اور عربی کے علاوہ فرانسیسی زبان پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے سیرۃ النبی پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب کا فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ عالمی زبانوں میں مہارت کی بدولت ہی انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کے دورے کیے اور وہاں اسلامی قوانین اور فقہ کے مختلف پہلوؤں پر فکر انگیز لیکچر دیے۔ ڈاکٹر محمود احمد دنیا کی مختلف جامعات سے بطور ممتحن بھی وابستہ رہے۔ وہ ایک بلند پایہ عالم دین، مستند فقیہ اور بالغ نظر دانشور کے طور پر ساری دنیا میں خاص شناخت کے حامل اور قابل احترام شخص تھے۔ ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ اور اتحاد بین المسلمین آپ کی زندگی کا مشن تھا۔ انہوں نے جدید تناظر میں مسلمانوں کے دینی و عصری چیلنجوں پر مدافعانہ، معذرت خواہانہ اور محض بیانیہ انداز اختیار کرنے کی بجائے ہمیشہ خالص معروضی و تجزیاتی اور منطقی و دانشورانہ انداز تحریر و بیان کو شیوہ بنائے رکھا۔ وہ عالم و دانشور جو صداقتوں کے متلاشی اور مبلغ ہوتے ہیں، وہ اپنی فکر و نظر کو وقتی مصلحتوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتے ۔ یہی کام ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا۔ انہوں نے توازن فکر اور فہم تاریخ و فقہ کی بنا پر ہمیشہ حقیقت پسندانہ موقف اختیار کیا۔ اپنی فکری و نظری سچائی اور قوت عمل کی بدولت انہیں زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا اور کیوں نہ گزرنا پڑتا کہؔ
سوداؔ جو بے خبر ہے کوئی وہ کرے ہے عیش
مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی
فکرو آگہی کے حامل دانشور کے طور پر وہ مسلمانوں کے عصری مسائل بالخصوص فرقہ واریت، انتہا پسندی اور فروعی مسائل پر جھگڑوں کے کبھی حامی نہیں رہے۔ وہ اﷲ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر تفرقوں سے بالا ہو کر امت مسلمہ کے اتحاد کے پیامبر و مبلغ تھے اور یہی اُن کی زندگی کا مشن اور نصب العین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عالمی و قومی سطح پر جس کانفرنس، سیمینار یا سمپوزیم میں جاتے، وہاں اتحاد بین المسلمین کے جذبے کا برملا اظہار کرتے اور فرقہ واریت کو زہر قاتل سمجھتے تھے۔ انہوں نے مختلف فقہی مسالک کو قریب لانے کے لیے ’’کاسمو پولیٹن فقہ‘‘ کا نظریہ پیش کیا تھا جس کو عام کرنے میں ذاتی حیثیت میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ بلا شبہ ملت اسلامیہ کو اپنی صحت شعور کے لیے آج جس بات کی اشد ضرورت ہے، وہ اسلام اور اپنے ماضی کے متعلق رومانیت و جذباتیت سے نکل کر خود تنقیدی کی نظر پیدا کرنا ہے تاکہ دھندلکوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے مستقبل کے لیے کوئی راستہ روشن ہو سکے۔ محض رومانیت و جذباتیت جہل کی وہ خطرناک قسم ہے جس سے ہر قسم کا ظلم پیدا ہوتا ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ عیاں ہوتا ہے کہ یہ درحقیقت ملی خود کشی کا راستہ ہے ۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی جیسے صاحبان نظر اپنے بیان و تحریر میں ملت اسلامیہ کو یہ انتباہ کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زبان و قلم سے دنیا کو حیات افروز اسلام سے متعارف کروانے کی مخلصانہ کوشش کی جو مایوسی نہیں امید ہے، تباہی نہیں تعمیر ہے، جو فرقہ واریت نہیں اتحاد ہے اور جو ناکامی نہیں کامیابی ہے ۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں ایک طرف آگاہ قلب اور روشن دماغ نمائندوں کو روشناس کرایا تو دوسری طرف قرآن و سنت، سیرت و حدیث، اسلامی سیاسیات و معاشیا،ت فقہ اور اقبالیات کے متنوع موضوعات پر عربی، انگریزی اور اردو میں درجنوں کتابیں رقم کیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیکچرز ، خطبات اور محاضرات کے مجموعے بھی مرتب ہوئے جن میں سے ’’مسلمانوں کا دینی و عصری نظام تعلیم‘‘ مرتبہ ڈاکٹر سید عزیز الرحمن کو الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ نے اہتمام خاص سے شائع کیا۔ اس میں ڈاکٹر محمود احمد غازی کے درج ذیل چھ خطبے شامل ہیں: (۱)دینی مدارس: مفروضے، حقائق، لائحہ عمل، (۲) قدیم و جدید تعلیم میں ہم آہنگی، (۳) مسلمانوں کی تعلیمی روایت اور عصر حاضر، (۴) اکیسویں صدی میں پاکستان کے تعلیمی تقاضے، (۵) مغرب کا فکری اور تہذیبی چیلنج اور علماء کی ذمہ داریاں، (۶) دینی مدارس میں تخصص اور اعلیٰ تعلیم و تحقیق۔ ان کے علاوہ دو فکر انگیز ضمیمے ’’مسلکی اختلاف اور اس کی حدود‘‘ اور ’’عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں‘‘ شامل ہیں۔ مرتب کے الفاظ میں ’’ ان میں سے ہر محاضرہ یا خطبہ اپنی جگہ ایک مستقل کتاب کی اہمیت رکھتا ہے۔..... انہوں نے اسلاف کی خطا شماری کو مقصود بنائے بغیر ماضی کا بے لاگ تجزیہ کیا ہے اور مستقبل کے لیے ہماری راہیں متعین کی ہیں‘‘۔
بلا شبہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی تحریروں اور محاضرات کا جائزہ لیں تو ان کی تحریریں محتاط تجزیے کے باوجود بے لاگ تبصرے اور دل میں اتر جانے والے حکیمانہ اسلوب کی حامل ہیں۔ وہ تنقید برائے تنقید کی بجائے تعمیری تنقید کے علمبردار ہیں۔ دلیل اور نیک نیتی سے لیس تحریریں اور درد مند دل کا بیان خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کی دستک نظر آتا ہے۔ تمام محاسن و خوبیوں سے بڑھ کر جو چیز ڈاکٹر صاحب کی علمی قامت کو مزید بلند او ران کے محققانہ و مدرسانہ کارناموں کو مزید وقیع اور معتبر بنا دیتی ہے، وہ ، وہ حالات ہیں جن میں انہوں نے توازنِ فکر و عمل کا علم بلند کیا اور تصنیف و تالیف اور تحقیق و تنقید کا کام جاری رکھا ۔ ان کے حوصلے اور جرات کی داد دینا ہو گی کہ انہوں نے کبھی خود پر اس یتیمانہ بے بسی کو طاری نہیں ہونے دیا جس سے اکثر ہمارے مذہبی دانشور دوچار رہتے ہیں۔
علم و تحقیق کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھنے والا یہ فکرمند اور درد مند دل ملت اسلامیہ کی حالتِ زار کی تاب نہ لا سکا۔ ۲۶ ؍ستمبر ۲۰۱۰ء کی شب ڈاکٹر محمود احمد غازی کو دل کی تکلیف ہوئی۔ انہیں اسلام آباد کے PIMS ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ عصر حاضر میں عالم اسلام کے اس قابل فخر فرزند کی نماز جنازہ اسی روز سہ پہر کو مولانا مشرف علی تھانوی نے پڑھائی او رانہیں اسلام آباد کے ایچ الیون قبرستان کے پلاٹ نمبر ۱۳ کی قبر نمبر ۱۳۶ میں سپرد خاک کر دیا گیا ۔ قبر پر تا حال کتبہ بھی نصب نہیں۔ آپ کے سوگواران میں بھائی ڈاکٹر محمد الغزالی، بیوہ اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں۔
آدم خاکی کو بالآخر آسودۂ خاک ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن دنیا سے رخصت ہونے والی ہستی اگر کوئی ایسی ہستی ہو جس نے اپنی زندگی کو تدریس و تحقیق اور دین و دنیا کی فلاح کے لیے وقف کیے رکھا ہو تو اس کا دنیا سے اٹھ جانا صرف ایک گھرانے یا خاندان کا نہیں، سب درد مند دل رکھنے والوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے ۔
اک گل کے مرجھانے پر کیا گلشن میں کہرام مچا
اک چہرہ کملا جانے سے کتنے دل ناشاد ہوئے
شیخ عبدالرشید
(ایڈیشنل رجسٹرار، یونیورسٹی آف گجرات )
( ۹ )
علامہ پروفیسر حافظ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ ہفت زبان عالم دین، محقق، اسلامی علوم کے ماہر تھے۔ وفاقی وزارت سے لے کر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی صدارت تک وہ کون سا عہدہ ہو گا جو انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے چھوٹے بھائی ممتاز عالم دین، اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی نے اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے ایک انٹرویو میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اظہار کرتے ہوئے کہا:
وہ ہمہ جہت شخصیت تھے۔ انہوں نے سرزمین پاکستان پر ۱۸؍ ستمبر ۱۹۵۰ء کو پاکستان کے ہائی کمیشن نئی دہلی میں آنکھ کھو لی۔ ہمارا خاندانی سلسلہ حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے۔ ہماری خاندانی روایات کے مطابق ہمارے خاندان کے مرد حضرات پر قرآن پاک حفظ کرنا لازم سمجھا جاتا ہے، یعنی حضرت عمرؓ سے ہمارے بیٹے حنظلہ غزالی تک سب مرد حضرات الحمدللہ حفظ قرآن شریف کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے چچا، تایا، کزن سب حافظ قرآن ہیں۔ اس روایت کے تسلسل کے طورپر ہم نئی دہلی سے کراچی آگئے تو برادر اکبر ڈاکٹر محمود احمد غازی نے بھی ۱۹۵۴ء میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانویؒ کے مدرسہ سے قرآن پاک حفظ کیا۔
بھائی صاحب نے اے کے بروہی کے سامنے تجویز پیش کی کہ اسلامی قوانین کے حوالے سے ایک ادارہ ہوناچاہیے، چنانچہ شریعہ فیکلٹی کا قیام قائد اعظم یونیورسٹی میں عمل میںآیا، لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کے ماحول میں یہ ادارہ ایڈجسٹ نہ ہوسکا۔ مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ رہے تھے جس پر مرحوم اے کے بروہی بھی پریشان تھے۔ انہوں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے؟ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے تجویز پیش کی کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے یہاں بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ انہوں نے عالمی اسلامی یونیورسٹی کی بنیادی تجویز مان لی۔ فیصل مسجد میں عالمی اسلامی یونیورسٹی کا منصوبہ کس طرح قابل قبول ہوا؟ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا موقف تھا کہ جس طرح عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر کا قیام بھی مسجد میں ہوا، اسی طرح یہ یونیورسٹی بھی فیصل مسجد میں قائم کی جائے۔ فیصل مسجد کا قیام کیسے ہوا؟ عالم اسلام کی اس منفرد عظیم الشان مسجد کی تعمیر ایک الگ داستان ہے۔ اس کا شرف شاہ فیصل شہید اورمملکت سعودیہ عربیہ کو جاتا ہے کہ یہ عظیم شاہکار اسلام آباد میں سامنے آیا۔
ایک اور بات جس پر بھائی صاحب سمیت ہم سب کو فخر حاصل ہے کہ عربی زبان، اسلامی علوم اور فقہ پرکامل دسترس رکھنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے بھائی صاحب کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ فیصل مسجد کے پہلے خطیب مقرر ہوئے۔ ان کی امامت میں ۲۲؍جون ۱۹۸۸ء کو پہلے جمعہ کے روز اس عالمی جامع کا افتتاح ہوا۔ مرحوم نے وہاں خطبہ دیا۔ بھائی صاحب نے دنیا کے قریباً تمام ممالک میں بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی۔ اپنے علم وفضل سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے جدید اسلامی، اصلاحی اور فلاحی نظریات سے تمام دنیا واقف تھی۔ جنرل پرویز مشرف بھی ان کے خیالات سے واقف تھے۔ وہ ان کے عہد میں ۲۰۰۴ سے ۲۰۰۶ء تک وفاقی وزیر مذہبی امور رہے۔ قطر کی بین الاقوامی یونیورسٹی کی طر ف سے جب پروفیسری کی پیش کش ہوئی تو اسے انہوں نے قبول کر لیا۔
غزالی صاحب کہنے لگے: میرے بھائی درویش صفت انسان تھے۔ وہ عالم باعمل تھے۔ وہ بہترین قاری اور حافظ قرآن تھے، چنانچہ انہوں نے کئی بار تراویح میں قرآن کریم سنایا۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی جو انہیں حاصل ہوئی۔ ان کی دلچسپی کا میدان اسلامی قانون، اسلامی معیشت وغیرہ تھے، لیکن تمام اسلامی علوم پر ان کی نظر بڑی وسیع او ر گہری تھی۔ اس کا ثبوت ان کا سلسلہ محاضرات ہے جس میں انہوں نے ۷ جلدوں میں مختلف اسلامی علوم کا مفصل تعارف کرا دیا ہے۔ یہ سلسلہ قرآن، حدیث، سیرت، شریعت، معیشت وتجارت اور اسلام کے بین الاقوامی قانون اور عصر حاضر کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے کو قارئین نے بے حد پسند کیا اور اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ اسی طرح ایک موقع پر ۱۹۸۵، ۱۹۸۷ء میں کئی سال کی محنت کے بعد وہ جنوبی ایشیا کی سپریم کورٹ میں پانچ ہفتے تک پیش ہو کر قادیانی مسئلہ پر اسلامی نقطہ نظر پیش کرتے رہے۔ اس موقع پر علما کی ایک ٹیم نے ان کی مدد کی۔ کورٹ میں ان کا بیان پانچ ہفتے تک جاری رہا اور پانچ ہزار صفحات لکھے گئے۔ اس میں عدالت اور وکیلوں کے تمام سوالات اور اعتراضات کا مدلل جواب دیا اور ختم نبوت کے بنیادی مسئلہ کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ اس کارروائی میں کئی برس صرف ہوئے مگر بھائی صاحب اس کام میں اس طرح کھپ گئے گویا زندگی میںیہی ان کا مشن ہو۔
اسی طرح پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ، اسلامی دستور کی تیاری اور عدالتی سطح پر، تعلیمی سطح پر، تصنیفی سطح پر اور پلاننگ کی سطح پر نفاذ شریعت کے لیے کوشاں رہے۔ میں نے انہیں زندگی بھر کسی بڑے سے بڑے حادثے کے موقع پر بھی روتے نہیں دیکھا، لیکن جب ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اس وقت مرحوم کی حالت ایسی تھی کہ انہیں سنبھالنا بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ ملک اللہ نے بغیر اسباب کے بنایا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ آزمائش کا وقت بھی گزر جائے گا۔
شریف فاروق /طاہر فاروق
(روزنامہ نوائے وقت ، لاہور، ۲۶؍ نومبر ۲۰۱۰ء)
( ۱۰ )
اسلام آباد (پاکستان ) کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر ڈاکٹر محمود احمد غازی کا ۲۶؍ ستمبر کو انتقال ہو گیا۔ ان کی رحلت نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ساری دنیائے علم و فکر کے لیے ایک سانحہ عظیم سے کم نہیں۔
۱۹۹۲ء میں جب پہلی مرتبہ میں اسلام آباد پہنچا تو ڈاکٹر صاحب دعوۃ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ اعلیٰ تھے۔ ان کا دفتر مسجد فیصل کامپلکس میں تھا۔ ہر جمعہ کو ان کا وہاں خطاب ہوا کر تا اور میں انہیں ایک اچھے خطیب کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اس کے دو سال بعد ہی ۱۹۹۴ء میں مجھے پھر اسلام آباد کا سفر درپیش ہوا اور قیام بھی طویل تھا۔ اس قیام کے دوران بھی میں نماز جمعہ مسجد فیصل میں ادا کیا کرتا تھا اور غازی صاحب کے خطاب سے فیض یاب ہوا کرتا۔ ایک دن ان سے باقاعدہ ملاقات ہو گئی۔ وہ جلد ہی میرے دوست بن گئے۔ مرحول دل کے فیاض تھے۔ انہوں نے اپنی اکیڈمی کی بہت سی قیمتی مطبوعات مجھے عنایت فرمائیں۔
ڈاکٹر غازی علم، ادب، سیاست ومعاشرت کے جس مسئلے پر گفتگو کرتے تو ان کی رائے بالکل واضح ہوتی تھی۔ ان میں ایک زندہ و تابندہ عالم کی شان نمایاں تھی۔ ایک موقع پر میں نے کہا کہ غازی صاحب ! آج کل ساری دنیا سے تحمل اٹھتا جا رہا ہے تو انہوں نے برجستہ کہا : کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ تحمل کی کمی واقع ہو رہی ہے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک صاحب سیرت انسان اور بلند پایہ عالم تھے۔ ان سے مختلف علمی موضوعات پر خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ خط کا جواب لکھنے میں وہ بہت باقاعدہ تھے۔ وہ ہندوستان کے سفر کی تمنا رکھتے تھے لیکن افسوس ہے کہ انہیں اس کا موقع نہ ملا۔ ڈاکٹر صاحب کے علمی کارناموں کی کوئی جامع فہرست تو اس وقت میسر نہیں ہے ۔ ان کی تازہ کتاب ’’ عصرحاضر اور شریعت اسلامی‘‘ کے عنوان پر انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے شائع کی ہے۔ یہ ایک انتہائی وقیع تحقیقاتی ادارہ ہے۔ اس کے سربراہ برادرم خالد رحمان صاحب چند ہی ماہ قبل مجھے یہ کتاب روانہ فرمائی تھی۔ اس قیمتی کتاب کی دستیابی پر ڈاکٹر غازی صاحب کو میں مبارک باد بھی نہ دے سکاکہ وہ راہی ملک عدم ہوئے۔ اس کتاب کے ڈسٹ کور پر ان کی خدمات کی جوتفصیل درج ہے، میں ان کو یہاں نقل کر رہا ہوں:
’’ڈاکٹر محمود احمد غازی انتقال سے قبل تک قطر فاؤنڈیشن ، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز میں شریعہ کے پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ اس سے پہلے آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر، پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور (اگست ۲۰۰۰ء تا اگست ۲۰۰۲ء ) ، نیشنل سیکورٹی کونسل حکومت پاکستان کے رکن (۹۹۔ ۱۹۹۸ء) ، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن، شریعہ اکیڈمی اور دعوۃ اکیڈمی اسلامی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل، فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب۔ موقرہ جریدہ ’’فکر ونظر‘‘ کے مدیر رہے۔ شریعہ بورڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیئرمین تھے( ۲۰۰۳تا حال) بہت سے پیشہ ورانہ اور علمی اداروں کی انتظامی اور علمی مجالس کے ممبر اور مشیر رہے۔ جن میں چند اہم یہ ہیں: عرب اکیڈمی شام، ابن رشد اسلامک یونیورسٹی اسپین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلا م آباد، بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بینک آف خیبر تکافل پاکستان۔
ڈاکٹر صاحب اسلامی قانون اور فقہ پر گہری نظر رکھنے والے چند اسکالرز میں سے تھے۔ جو عصرحاضر میں درپیش مسائل سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ ۲۳کتب اور ۱۰۰ سے زیادہ مقالات کے مصنف ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک ہونے والی ۱۰۰ سے زائد بین الاقوامی علمی کانفرنسوں میں شرکت کر چکے تھے۔ انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد کی نیشنل اکیڈمک کونسل کے رکن تھے۔ آپ کی تصانیف میں محاضرات قرآن، محاضرات سیرت، محاضرات فقہ، محاضرات حدیث ، اور اسلام کا قانون بین الممالک قبولیت عام حاصل کر چکی ہیں‘‘
ڈاکٹر محمود احمد غازی نے ’’عصر حاضر اور شریعت اسلامی‘‘ کے موضوع پر جو خطبات دیے تھے ، ان کی تعداد آٹھ ہے۔ ہر خطبے کے لیے ایک فاضل شخصیت کی صدارت طے کی گئی تھی۔ خطبے کے اختتام پر سوال وجواب کا سلسلہ کچھ دیر چلتا ر ہتا تھا۔ چنانچہ پانچواں خطبہ ’’ اسلامی شریعت ، مسلم معاشرہ ، ملکی وانتظامی امور اور بین الانسانی معاملات ‘‘ کے موضوع پر منعقد کیا گیا کہ ’’ کہ آج ایک مکمل اسلامی ریاست قائم کرنے کا سب سے آسان اور عملی طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ:
’’ اس کا سب سے آسان طریقہ دعوت وتبلیغ اور رائے عامہ کی تیاری ہے۔ مسلمان اسلامی ممالک میں جتنی مضبوط اور وسیع رائے عامہ اسلامی ریاست کے حق میں ہو گی، اتنی ہی جلدی اسلامی ریاست قائم ہو گی۔ نہ صرف عامۃ الناس اس بارے میں شدید غفلت کا شکار رہے ہیں بلکہ اہل علم نے بھی ان کی مناسب رہنمائی اور تربیت میں خاصی کوتاہی کی ہے۔ اگر اسلامی ریاست عامۃ الناس کا مسئلہ نہ ہو ، عام لوگ اس سے الگ تھلگ رہیں اور کچھ محدود لوگ اسے اپنامسئلہ قرار دے کر محدود انداز سے کام کرنے پر اکتفا کریں تو اسلامی ریاست قائم نہیں ہو گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ اس کام کے لیے اٹھیں گے وہ اپنی محدود تعداد اور عامۃ الناس کی عدم دلچسپی اور عدم شرکت کی وجہ سے امت سے الگ سمجھے جائیں گے اور اسلامی ریاست کا مسئلہ ان کا گروہی مسئلہ قرار دے دیا جائے گا کہ فلاں گروہ یا فلاں صاحب کا مسئلہ ہے لیکن اگر پوری امت کی رائے عامہ مکمل طور پر بیدار ہو اور پورے ملک کا یا مسلم اقوام کا یہ مسئلہ ہو تو پھر اسے کسی طبقے کامسئلہ قرار دے کر نظر انداز کر دینا دشوار ہو جائے گا‘‘۔ (عصر حاضر اور شریعت اسلامی ص۲۱۴۔۲۱۵)
موجودہ حالات میں محمود احمد غازیؒ کے اسی پیغام دانشورانہ پر امت مسلمہ کو غوروفکر کرنا چاہیے۔ مرحوم کے قابل رشک کارناموں کے باوجود اسلامی دنیا کو ابھی ان سے بڑی توقعات تھیں۔ خلاف توقع وہ اپنے اعزہ، احباب ومخلصین اور دیگر شیدائیوں کی بھری محفل سے کچھ اس طرح رخصت ہوئے کہ غالب کی زبان میں
جاتے ہوئے کہتے ہو، قیامت کو ملیں گے
کیاخوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور ؟!
وحید الدین سلیم
حیدر آباد ، بھارت
(بشکریہ سہ روزہ ’’دعوت ‘‘ دہلی)
( ۱۱ )
استاد ہونا قابل اعزازہے، لیکن اس اعزاز کے تقاضے بھی زیادہ ہیں۔ڈاکٹر محموداحمدغازی مرحوم کو اللہ نے جہاں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہاں وسعت قلبی اورنرم مزاجی بھی عطا فرمائی تھی۔ بالخصوص طلبہ کے لیے ان کا رویہ حدردرجہ نرمی ومہربانی کا رہتا تھا۔ مشکل سے مشکل اور عمیق ودقیق علوم کو سامع کی ذہنی وعلمی سطح کے مطابق حل کر کے سمجھادیناغازی صاحب کا امتیازی ملکہ تھا۔ سامع یا سائل کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھنا کتنامفید ہوتاہے، اس کی مثال خود دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سابق صدر پرویزمشرف کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آپ کی یونیورسٹی میں طلبہ وطالبات کو علیحدہ علیحدہ کلاسوں میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ توآج کی روشن خیالی کے بالکل خلاف ہے، اس کوختم ہونا چاہیے۔ جواب میں غازی صاحب کہتے ہیں کہ میں اگرو ہاں علمی دلائل پیش کرتا تو بات کبھی ان کی سمجھ میں نہ آتی۔ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ پردہ کرنے کو اچھا سمجھتا ہے اور پردہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، لہٰذا جہاں بہت سے ادارے ایسے ہیں جن میں مخلوط تعلیم کا اہتمام ہے، وہاں اگر کچھ تعلیمی ادارے ایسے بھی ہو ں جہاں پردے کا اہتمام ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ غازی صاحب کہتے ہیں، یہ بات فوراً ان کی سمجھ میں آگئی اور ان کا اشکال دور ہو گیا۔
ایک شفیق استاد کے لیے یہ بات ناقابل تحمل ہوتی ہے کہ اس کی بات اس کے شاگرد کی سمجھ میں نہیں آئی، چنانچہ ایک مرتبہ ایم فل علوم اسلامیہ کی ایک ورکشاپ میں غازی صاحب کا لیکچر ہوا۔ ایک گھنٹہ تیس منٹ کے لیکچر کے بعد سوال وجواب شروع ہوئے تو غازی صاحب کو ادراک ہوا کہ آخر کی صفوں میں دو غیر ملکی طالب علم ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اردو نہیں آتی تھی۔ چنانچہ غازی صاحب نے دوبارہ سارا لیکچر عربی زبان میں دہرا دیا۔غالباً یہی وہ خصوصیت تھی جس کی بناپر اللہ تعالیٰ نے غازی صاحب کو نہ صرف طلبہ کے دِلوں میں بلکہ معاصر اساتذہ کے دلوں میں بھی وہ مقام عطا فرمایاجس کی تمناکرنا توآسان ہے، لیکن اس کا حصول بہت صبر آزما ہے۔
راقم الحروف کا غازی صاحب سے تعلق قرابت داری کے علاوہ شاگردی کا بھی رہا۔ مختصر وقت میں مشکل اور دقیق مباحث کو بڑی آسانی سے بغیر کسی ڈائری کے صرف اپنی یادداشت اور مطالعہ کی بنیادپر اس طرح بیان فرماتے تھے گویا ابھی کچھ ہی دیر پہلے تازہ مطالعہ کر کے آئے ہیں۔ مختلف اسلامی علوم وفنون کاتاریخی ارتقا اس طر ح بیان کرتے تھے کہ سامع کو لگتاتھاکہ یہ سارا کام ان کے سامنے ہواہے اور وہ اپنے مشاہدہ کو بیان کررہے ہیں۔ غازی صاحب کے مطالعہ میں وسعت اور گہرائی واضح جھلکتی تھی۔ ان کے لیکچر میں بیٹھے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا۔ ان کاہر لیکچر اپنے موضوع پر جامع گفتگو ہوتی تھی۔ پاکستان میں رسم عثمانی کے مطابق مصحفِ قرآ نی کی ضرورت واہمیت کے موضوع پر راقم الحروف کی غازی صاحب سے ان کے گھر پر گفتگو ہوئی۔ پچاس منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں غازی صاحب نے تقریباً چالیس منٹ تک مکمل اطمینان اور دلچسپی سے پوری گفتگو سنی۔ اس کے بعد فرمایاکہ آپ اس کی مکمل رپورٹ بناکر مجھے ارسال کر دیں۔ گفتگو کے دوران غازی صاحب نے ایک لمحہ بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کا وقت قیمتی ہے، لہٰذا بات کو مختصر کیا جائے، بلکہ ان کی دلچسپی بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔
ان کے زمانہ وزارت میں بھی طلبہ کو ان سے رہنمائی لینے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ راقم کو ایک سوال کے سلسلے میں ملنے کی ضرورت پیش آئی تو ان کے دفتر میں چلا گیا۔ اسٹاف نے بتایاکہ ان کی مصروفیات آج کل زیادہ ہیں، لہٰذا شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ راقم نے سوال ایک کاغذ پر لکھااور ان کی میز پر رکھ کر خود لائبریری میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو واپس دفتر میں آکر پوچھا تو اسٹاف نے بتایا کہ چند منٹ کے لیے آئے تھے، پھر کسی میٹنگ میں چلے گئے ہیں۔ راقم نے مایوس ہو کر سوچاکہ اپنا لکھا ہوا سوال واپس اٹھا لیتا ہوں۔ کاغذ اٹھایا تو اس پر مکمل جواب لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ غازی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین!
حافظ رشید احمد تھانوی
(جامعہ دار العلوم الاسلامیہ، لاہور)
( ۱۲ )
سابق وفاقی وزیر مذہبی امور اور ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک سچے عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تعلیم بھی تھے۔ والد گرامی مولانا منظور احمد چنیوٹی ؒ سے ان کا گہرا تعلق مذہبی حوالے سے ایک مستقل باب ہے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود اپنے سینے میں مذہب کے لیے تڑپنے والا ایک دل رکھتے تھے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک عرصے تک صدر رہنا ان کے علم سے شغف کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سلسلے میں ان کی گراں قدر خدمات تاریخ کا ایک حصہ ہیں اور تعلیم یافتہ طبقہ پر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے، نیز یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ملکی سطح پر مذہبی حوالے سے جب بھی کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوتا یا مسائل ومشکلات درپیش ہوتیں تو حضرت والد گرامی فوری طور پر ان کے ساتھ را بطہ کرتے اور صورت حال سے آگاہ کرنے کے بعد ان کے صائب مشوروں کی روشنی میں اس کا حل نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے۔ راقم الحروف کی والد صاحب کی معیت میں ان سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور غالباً چند ملاقاتیں ان کے علاوہ بھی ہیں۔
ایک ملاقات میں ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے والد صاحب ؒ نے ان سے کہا کہ قادیانی کافر ہیں اور وہ سعودی عرب میں اپنی مذہبی اور دیگر خلاف اسلام کار روائیاں کرتے ہیں، اس لیے حکومت سعودیہ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن وہ دھوکہ دہی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ پاسپورٹ شناختی کارڈ کی بنیاد پر بنتا ہے اور اس میں مذہب کے خانے کا اندراج نہیں ہے، لہٰذا شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے یا پھر مسلم اور غیر مسلم کے شناختی کارڈ کا رنگ تبدیل کر دیا جائے، جیسا کہ سعودیہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ’’اقامہ‘‘ کا رنگ الگ الگ ہے۔ اس تجویز کو ڈاکٹر صاحب نے بہت پسند کیا اور ارباب بست وکشاد کے سامنے مسئلہ رکھنے کا وعدہ کیا۔
ایک دوسری ملاقات میں والد صاحبؒ نے ڈاکٹر صاحب ؒ کے سامنے ایک دوسرا مسئلہ بھی پیش کیا کہ چناب نگر قادیانیوں کی نام نہاد ریاست ہے۔ وہاں کے تمام لوگ قادیانیوں کے زیر تسلط ہیں۔ ان کی زمینوں اور جائیدادوں کے کاغذات ملکیت رہائشیوں کے پاس نہیں، بلکہ وہاں کے ناظم جماعت اور صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ جب چاہیں، انہیں بے دخل کر دیتے ہیں۔ اب جو بھی کوئی قادیانی مسلمان ہو نا چاہے تو اس کے اسلام لانے میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے سامان، مکان، زمین اور جائیداد وغیرہ پر قبضہ کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں اور خود ناجائز طور پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ باوجود خواہش اور کوشش کے مسلمان نہیں ہو سکتے، لہٰذا چناب نگر کے رہائشیوں کو مالکانہ حقوق دلوانے کے لیے کوشش کی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قادیانیوں کی ایک کثیر تعداد مسلمان ہو جائے گی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ آگے بڑھایا تو مختلف محکموں میں موجود قادیانی لابی نے اس کیس کو دبا دیا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں۔ اب یہ کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ کئی دفعہ قادیانی سازشوں کی وجہ سے جج تبدیل ہوتے رہے یا کیس خارج کروا دیا جاتا رہا۔ اب ہماری طرف سے نظر ثانی کی اپیل چل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کیس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے تو اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہو ں گے۔
ختم نبوت سے ان کے دلی لگاؤ کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ والد صاحب کی مشہور زمانہ کتاب ’’ردقادیانیت کے زریں اصول‘‘ کے شروع میں ڈاکٹر صاحب کی ایک شاندار اور پر مغز تقریظ موجود ہے جس نے کتاب کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تقریظ اس اشاعت میں شامل کرنے کی غرض سے ارسال کی جار ہی ہے۔ اس تقریظ سے ختم نبوت کے ساتھ ان کی وابستگی اور حضرت والد مرحوم کے مشن کے ساتھ لگاؤ بھی ظاہر ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب ؒ جیسی شخصیات تو اب چراغ لے کر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتیں۔ اگر ایسی چند مزید شخصیات ڈاکٹر صاحب کو میسر آ جاتیں تو ان کا تعاون حکومتی سطح پر ان کو بہت کارآمد ثابت ہو تا، لیکن قدرت نے ان کو مزید مہلت نہ دی اور وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ قدرت کویہی منظور تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مشن مکمل کرنے کی صلاحیت سے نوازیں، تاکہ ان کے صدقات جاریہ اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مولانا ثناء اللہ چنیوٹی
( ادارۂ مرکزیہ دعوت وارشاد، چنیوٹ)
( ۱۳ )
شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب ؒ کے شاگرد رشید، جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن، راجہ بازار راولپنڈی کے فاضل، جامعہ اشرفیہ لاہور اور جامعۃالعلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے متعلم، وفاقی شرعی عدالت کے جج، اسٹیٹ بینک کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے سابق صدر، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور، بالغ نظر محقق، بہترین صاحب قلم، مختلف زبانوں میں تدریس و خطابت کے شہسوار، عالمی شہرت یافتہ شخصیت، علمی رسوخ کے حامل، وطن عزیز کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر محمود احمدغازی ۱۶؍ شوال ۱۴۳۱ھ/۲۶؍ ستمبر ۲۰۱۰ء بروز اتوار بعد نماز فجر ۶۰ سال کی عمر میں راہی عالم آخرت ہو گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔
ڈاکٹر محمود احمدغازی کا نسبی تعلق کاندھلہ کے ممتاز علمی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد محترم بزرگوں کے صحبت یافتہ متدین ومتبع سنت بزرگ تھے۔ ڈاکٹر غازی صاحب ؒ نے درس نظامی کی ابتدائی تعلیم جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، کراچی میں حاصل کی۔ پھر آپ کے والد محترم اسلام آباد منتقل ہو گئے تو آپ نے لاہور جاکر جامعہ اشرفیہ میں داخلہ لے لیا اور آخرمیں جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں درس نظامی کی تکمیل فرمائی اور شیخ القرآن حضرت اقدس مولاناغلام اللہ خان صاحبؒ سے خصوصی طور پر تلمذ کا شرف حاصل فرمایا۔ درس نظامی کی تکمیل کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مراحل طے کر کے اعلیٰ سندات حاصل کیں۔
ڈاکٹر صاحب بفضلہ تعالیٰ اسلامی وعصری علوم میں زبردست استعداد کے حامل تھے۔ انہوں نے حضرت مولاناغلام اللہ خان ؒ کی زیرنگرانی درس نظامی کی تکمیل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سترہ سال کی عمر سے ہی ڈاکٹر صاحبؒ نے تدریس کا آغاز فرما دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی شرعی و عصری دونوں طرح کے علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی، لیکن جدیدعصری فنون وافکار سے وافر آگاہی کے باوجود آپ میں تجدد یا کسی فکری زیغ کا کوئی شائبہ نہیں تھا اور بظاہر یہ خاندانی اور دینی مدارس کی تعلیم وتربیت کا ثمرہ ہی تھا کہ آپ دینی تصلب اور علمی رسوخ کے حامل تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود ان کی کسی ادا میں ڈھونڈ کر بھی اپنے علم یا خدمت پر ناز یا فخر کی کوئی پرچھائیں تلاش نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب ایک سادہ، متواضع، منکسر المزاج اور ہنس مکھ انسان تھے۔ رمضان المبارک میں ہر سال اہتمام سے تراویح میں قرآن کریم سناتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب حق کی ترجمانی کرنے والے انسان تھے۔
عالمی کانفرنسوں میں غیر مسلموں کے سامنے آپ دین اسلام کی ترجمانی معتقدات اسلام کی حقانیت، اسلامی احکام و تعلیمات کے دفاع کے لیے پیش پیش رہے۔ ڈاکٹر صاحب معاند خیالات ونظریات او ر زیغ وضلال کے فتنوں کا تعاقب کرنے والے مرد مجاہد تھے۔ انھوں نے پاکستان کے آئینی وقانونی مسائل میں بھرپور رہنمائی دی، جب کہ جنوبی افریقہ کی غیرمسلم عدالت میں قادیانیوں کے خلاف کیس لڑ کر اس تاریخی مقدمہ میں ملت اسلامیہ کے موقف کو سرخرو کرتے ہوئے اسے پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کی عدالتوں کے لیے مثال بنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ خدمت تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
ڈاکٹر صاحب نے قرآن، حدیث، سیرت، فقہ وقانون، معیشت وتجارت، اور دیگر علوم وفنون پر ۲۵ سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں ۔ آپ کی تصانیف اہل علم اور نئی نسل کے لیے قیمتی تحفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رضا ورضوان کا معاملہ فرمائیں۔
مولانا سید محمد زین العابدین
(مدرسہ امام ابویوسف، شاد مان ٹاؤن ، کراچی)
( ۱۴ )
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے بڑے مشفق استاد تھے۔ میرا ان سے پہلا تعارف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک کوڈ کا ٹیوٹر مقرر ہونے کے لحاظ سے ہوا۔ وہ ہماری کتاب ’’تحقیق نگاری‘‘ کوڈ نمبر ۷۱۴ کے ٹیوٹر مقرر ہوئے تھے۔ ۱۹۸۹ء میں ہمیں اوپن یونیورسٹی نے اسلام آباد میں ورکشاپ کے لیے بلایا۔ ابتدائی طور پر کل طلبہ کی تعداد ۶۵ تھی۔ ان میں سے کچھ فیل ہوئے اور بعض نے چھوڑ دیا تو ورکشاپ کے وقت ۳۵ طلبہ رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحبؒ کا کورس سب سے مشکل تھا، یعنی تحقیق نگاری جس میں طلبہ کو تحقیقی مقالے کا خاکہ تیار کرنا تھا۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے جب طلبہ کا رزلٹ دیا تو ۳۵ میں سے ۲۵ طلبہ فیل ہو گئے۔ صرف دس طلبہ پاس ہوئے، میں بھی پاس طلبہ میں سے تھا۔ بہت پریشانی ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ ان میں کچھ بڑی عمر کے حضرات بھی تھے۔ ان میں ڈاکٹر محمد نواز چودھری تھے جن کی تقابل ادیان کی کتاب ہم ایم اے کے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی سب فیل ہو گئے۔ اتفاق سے میں پاس ہو گیا۔ سب ساتھیوں نے مجھے گھیر لیا کہ آپ چونکہ پاس ہیں، اس لیے ڈاکٹر صاحبؒ سے ہماری سفارش کریں کہ ہمیں بھی پاس کر دیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ کچھ کام کر کے لے آئیں گے تو وہ پاس کریں گے۔ ایسے میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ ان کے گھر تو چلیں، آپ ہماری وکالت کریں۔
ہم نے ڈاکٹر صاحبؒ سے وقت لیا اور انھوں نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے وقت دے دیا۔ سب لوگ چار بجے ان کے گھر پر پہنچے۔ سپر مارکیٹ کے قریب ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت پرتکلف چائے پلائی۔ پھر کہنے لگے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے دبی سی آواز میں کہا کہ ہم ایک ’’ترلہ کمیٹی‘‘ لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قہقہہ لگا کر بہت ہنسے۔ کہنے لگے کہ کیا بات ہوئی؟ پھر میں نے سب کی طرف سے عرض کیا کہ آپ نے معزز اساتذہ کرام کو فیل قرار دے دیا ہے۔ اب یہ کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ اسی دوران ایک صاحب، جن کی عمر ۵۵ سال کے لگ بھگ تھی، کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب! جب آپ کا خط میرے گھر میں پہنچا تو میرے بیٹے نے گھر میں شور مچا دیا کہ امی! ابو فیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ؒ نے پھر قہقہہ لگایا اور کہنے لگے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب میں فیل کر چکا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ محترم اساتذہ کرام کو دو دن دے دیں، یہ اپنا کام درست کر لیتے ہیں۔ آپ پھر اس کی جانچ کریں اور ان میں جس کو پاس کرنا ہو، کر دیں۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے وعدہ کر لیا۔ دو دن میں اساتذہ نے خاصی محنت کر کے اپنے کام کو بہتر کیا، خاکہ اچھے انداز سے تیار کیا اور ڈاکٹر صاحب نے واقعتا ان کو پاس کر دیا۔ اس سے بہت سے اساتذہ کا وقت بچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب ؒ اس قدر مشفق تھے۔
میرا ان کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نے ان کو بورڈ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کا ممبر بنایا تو مجھے ان کے سامنے پیش ہونا تھا۔ ڈاکٹر عبدالمالک عرفانی مرحوم مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے تھے۔ اگرچہ بنیادی طور پر وکیل تھے، تاہم اچھے انسان تھے۔ ’’اسلام کا نظریہ ضرورت اور جدید قانون میں اس کی حیثیت‘‘ کے عنوان سے ۱۹۸۴ء میں ان کا پی ایچ ڈی کامقالہ پنجاب یونیورسٹی سے منظور ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے موضوع دیا اور خاکہ تیار کرایا اور کہا کہ آپ ’’ اسلام کا نظریہ ضرورت اور پاکستان کے سیاسی بحرانوں میں اس کے استعمال کا جائزہ‘‘ پر کام کریں۔ میں سارا کچھ تیار کر کے لے گیا۔ اب جو حضرات میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ڈاکٹر غازیؒ بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے کہا کہ ان کا مقالہ کیسے پاس ہوگا، ان کا موضوع تو اسلامیات رہا ہی نہیں، اس لیے یہ مسترد کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی نیا عنوان سوچیں اور اس پر خاکہ تیار کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے اسی وقت مجھے نوٹ کرو ایا: ’’پاکستان کا نظریہ ضرورت اور مسلم سیاسی فکر کے ارتقا میں اس کا کردار‘‘۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علمی سرمایہ ہوتا ہے، ان کا ذہن کتنا کام کرتا ہے۔ واقعتا مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن میں نے اسے نوٹ کر لیا۔
رات کومیں اپنے اقارب کے گھر میں مقیم تھا۔ میں نے ڈاکٹر عبدالمالک عرفانی سے کہا کہ میرا عنوان تو مسترد ہو گیا ہے اور ڈاکٹر محمودغازی نے یہ عنوان دیا ہے ۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو کیسے لکھیں گے۔ دس صفحات سے زیادہ مواد نہیں ملے گا۔ میں خاصا پریشان ہوگیا ۔عرفانی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹر غازی صاحب سے دوبارہ پوچھیں کہ اس پر کس انداز سے آگے چلنا ہے اور کیا لکھنا ہے؟ میرے پاس ڈاکٹر صاحبؒ کے گھر کا ٹیلی فون کا نمبر تھا۔ اسی وقت میں نے رابطہ کیا اور ڈاکٹر صاحب سے بات کی۔ ڈاکٹر صاحبؒ کہنے لگے کہ خلافت راشدہ تک تو سب خیریت تھی۔ اس کے بعد بنوامیہ آئے تو ہم نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی قابل قبول ہے۔ ہم نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ پھر بنوعباس آئے۔ ہم نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے اور ان کا حکم ماننا شروع کر دیا۔ پھر عثمانی خلافت کا دور آیا تو ہم نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر جدید دور کے صدر اور وزیرا عظم آ گئے تو ہم نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سیاسی فکر کا ارتقا ہوا۔ اس طرح آپ نے آگے چلنا ہے۔ میں خاصا مطمئن ہو گیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر عرفانی صاحب سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ گائیڈ لائن دی ہے۔ کہنے لگے ، ٹھیک ہے۔ آپ کام کریں۔ بہرحال میں نے جب کام کرنا شروع کیا تو میرے پاس تقریباً دوہزار صفحات کا مواد تھا۔ پھر میں نے اس میں تحدید کی۔ میں نے اپنا مقالہ ڈاکٹر صاحبؒ کو پیش کیا تو انھوں نے کہا کہ آپ جمع کرا دیں۔ اس طرح میں پاس ہو گیا اور مجھے ڈگری مل گئی۔
ڈاکٹر صاحبؒ علمی حوالہ سے بہت زیادہ ’’امیر آدمی‘‘ تھے، rich minded تھے۔ ان کے انتقال کی جب مجھے خبر ملی تو بڑا دکھ ہوا اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اچھی جگہ عنایت فرمائے۔ ہمیں ان کے افکار سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
ڈاکٹر شریف چودھری
(ر) ایسوسی ایٹ پروفیسر،
گورنمنٹ کالج، گوجرانوالہ
( ۱۵ )
ممتاز علمی سکالر ،مذہبی دانشور او ر عالم اسلام پر گہری نظر رکھنے والے عظیم مفکر ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ ہمیں داغ مفارقت دے کر خود راہی آخرت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی بہت زیادہ خوبیوں کے مالک تھے۔ دینی و عصری علوم کے ماہر، اسلامی موضوعات کے محقق اور دورجدید میں پیش آمدہ مسائل اور عالم اسلام کے حالات وواقعات اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ایک بیدار مغز انسان تھے۔ وہ اپنی انھی خوبیوں اور خداداد صلاحیتوں کی بدولت اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ وفاقی وزارت مذہبی امور، شریعت جج ، اسلامی نظریاتی کونسل اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اہم مناصب ان کے سپرد کیے گئے جو انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے احسن طریقہ سے نبھائے اور خدمات سرانجام دیں۔ ڈاکٹر غازی مرحوم صرف کسی مخصوص طبقے تک محدود نہ تھے بلکہ علماء دیوبند میں بھی شرف و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور اہل مدارس آپ کو اپنے پروگراموں میں دعوت دے کر آپ کی گفتگو سننے اور اپنے لیے فخر سمجھتے، چنانچہ دارالعلوم کراچی، جامعۃالرشید، جامعۃ الخیر لاہور اور الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ کے علاوہ بیشتر مدارس کی تقریبات میںآپ تشریف لاتے، جید اور ممتاز علماء کرام کے درمیان خطابات فرماتے اور اپنی رائے سے نوازتے۔ اکابر علماء بھی آپ کی رائے کا احترام کرتے۔ استاذ گرامی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ نے ایک دفعہ ’’حجۃ اللہ البالغہ‘‘ کے درس کے دوران فرمایا کہ اس وقت میر ی نظر میں برصغیر میں دو شخصیات ایسی ہیں جو مغرب کو آج کے دور کی زبان میں حجۃ اللہ پڑھا سکتے ہیں اور امام شاہ ولی اللہ ؒ کا فلسفہ سمجھا سکتے ہیں۔ ان میں اول شخصیت مولانا مفتی محمدتقی عثمانی مدظلہ اور دوسری ڈاکٹر محمود احمدغازی ہیں۔ اس سے ڈاکٹر صاحب کے علمی مقام ومرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
راقم نے پہلی بار ڈاکٹر صاحب کی زیارت کا شرف اپنی مادر علمی جامعہ اسلامیہ کامونکی میں کیا۔ استاذ گرامی مولانا عبدالرؤف فاروقی، جو مذاہب عالم اور تقابل ادیان پر خوب دل جمعی سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے قائم کردہ ادارہ جامعہ اسلامیہ کامونکی میں ایک عمارت اسی کام کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ مختلف اوقات میں تقابل ادیان کے حوالے سے مختلف کورسز کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔انہوں نے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ سے منسوب ہال کی افتتاحی تقریب رکھی جس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم تھے۔ اس سیمینار میں مولانا سمیع الحق، قاضی عبداللطیف، مولانا زاہدالراشدی، مولانا اجمل قادری اور دیگر علما تشریف فرما تھے۔ ڈاکٹر غازی صاحبؒ تقریر کیا کر رہے تھے، علم کا سمندر بہا رہے تھے اور ان کی گفتگو میں اس قدر تسلسل اور ربط تھا کہ اتنی طویل گفتگو راقم سمیت دیگر حاضرین نے پوری دل جمعی اور توجہ سے سنی۔ اس موقع پر ہم ڈاکٹر عزیر الرحمن کے بے حدمشکور ہیں جنھوں نے ڈاکٹر صاحبؒ کی متعدد تقاریر قلم بند کر کے ’’اسلام اور مغرب تعلقات‘‘ کے نام سے مجموعہ شائع کیا۔مذکورہ تقریر اسی مجموعے میں شامل ہے۔
حافظ خرم شہزاد
(اقرا روضۃ الاطفال، گوجرانوالہ)
( ۱۶ )
ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ ڈاکٹر حمید اللہ ؒ کے بعد اسلامی دنیا کے بڑے مذہبی اسکالر تھے۔ آپ کے لیکچرز بہت پسند کیے گئے ہیں اور وہ کتابی شکل میں دستیاب ہیں۔ محترم غازی صاحبؒ نے اپنے کیریئر کا آغاز ادارہ تحقیقات اسلامی سے کیا اور مختلف حیثیتوں میں خدمات انجام دیتے ہوئے دعوہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل ، خطیب فیصل مسجد ، نائب صدر اسلامی یونیورسٹی اور ۲۰۰۴ء سے ۲۰۰۶ء تک صدر اسلامی یونیورسٹی رہے۔ غازی صاحب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بیک وقت مختلف سات زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ جامعہ تعلیم القرآن، راولپنڈی سے درس نظامی مکمل کیا۔ بعدازاں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ڈاکٹر صاحب نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت، محاضرات فقہ، محاضرات معیشت وتجارت، اسلام کاقانون بین الممالک، حیات مجدد الف ثانیؒ اور سنوسی تحریک۔
ڈاکٹر صاحب نے سیرت پر ڈاکٹر حمیداللہ کی فرانسیسی میں لکھی گئی کتاب کو انگریزی میں ایڈٹ اور ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ ایک ہمہ جہت اور ہمہ پہلو شخصیت تھے جو قدیم اور جدید علوم کا حسین امتراج تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کاایک ایک لمحہ دین کی ترویج و اشاعت، اقدار اسلامیہ کے فروغ اور ملک و ملت کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ اسلامی تعلیمات ڈاکٹر صاحب کے رگ وپے میں سرایت کیے ہوئے تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کا علم سمندر کی سی گہرائی رکھتا تھا۔ اخلاق کریمانہ سے متصف تھے اور ہر ملنے والے سے ایسے ملتے تھے گویا وہ دیرینہ شناسا ہو۔
ڈاکٹر صاحب اس ورثے کے امین تھے جو سراپا علم تھا کہ والد کی طرف سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے اور والدہ کی طرف سے مولانا محمد الیاسؒ بانی تبلیغی جماعت سے قرابت داری تھی۔ آپ وفاقی وزیر بھی رہے اور وقت کے ڈکٹیٹر کے ساتھ نظریاتی اختلاف بھی رکھا اور جب اس ڈکٹیٹر نے دینی حکمت عملی میں تبدیلی کی تویہ کہتے ہوئے وزارت سے استعفا دے دیا کہ مجھے یہ تبدیلی منظور نہیں۔ غازی صاحب کاوصال کسی ایک طبقہ، خاندان یا ایک ملک کا نقصان نہیں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا نقصان ہے۔
نعمت اللہ سومرو
(ڈگری کالج ، نوشہرو فیروز ،سندھ)
( ۱۷ )
انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیوں سے نوازا ہے اور بعض کو بعض پر درجات وکمالات میں امتیاز واختصاص پر فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر محمود احمد غازی کے ساتھ بھی درجات و کمالات میں امتیاز و اختصاص کا منفرد معاملہ وبرتاؤ فرما رکھا تھا۔ آپ بیک وقت حافظ قرآن، ممتاز عالم دین اور عصری علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ آپ کو علما، طلبہ، عوام الناس او ر سیاست دان حضرات قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پختہ حافظہ اور فہم وتدبر کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ مختلف زبانوں میں تدریس کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ بہت گہرائی میں گفتگو فرماتے، مختلف کتابوں کے حوالے اور مراجع کی نشان دہی فرماتے، پھر مختلف مسائل میں ائمہ کرام ومحدثین عظام ؒ کی مختلف آرا پیش نظر وزیر بیان ہوتیں۔ ان متنوع سلسلوں کے باوجود آپ کے بیان میں اور تقریر میں تسلسل متاثر نہیں ہوتا تھا۔ اسے یقیناًوہبی کمالات کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے۔
جب آپ کسی موضوع پر بیان فرماتے تو اپنے موضوع سے ہٹتے نہیں تھے بلکہ اس موضوع کی گہرائی میں جاتے تھے، کیونکہ آپ کا مطالعہ اور معلومات بہت وسیع تھیں۔ آپ کے جتنے خطبات ہیں، ان میں سے اکثر خطبات کتابی صورتوں میں آچکے ہیں جن کو ’’الفیصل تاجران کتب لاہور‘‘ نے شائع کیا ہے۔ مثلاً محاضرات سیرت، محاضرات قرآنی، محاضرات فقہ، محاضرات حدیث وغیرہ۔ ان محاضرات میں اچھا خاصا علمی مواد موجود ہے جن کو قاری پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔
محاضرات حدیث میں ان موضوعات کا ذکر ہے: علم حدیث کا تعارف، علم حدیث کی ضرورت واہمیت ،حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت، روایت حدیث اور اقسام حدیث، علم اسناد ورجال، جرح وتعدیل، تدوین حدیث، رحلہ اور محدثین کی خدمات، علوم حدیث، کتب حدیث و شروح حدیث، برصغیر میں علم حدیث، علم حدیث دور جدید میں۔
محاضرات فقہ میں ان موضوعات کا ذکر ہے: فقہ اسلامی: علوم اسلامیہ کا گل سرسبد، علم اصول فقہ: عقل ونقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ، فقہ اسلامی کے امتیازی خصائص، اہم فقہی علوم اور مضامین کا تعارف، تدوین فقہ اور مناہج فقہا، اسلامی قانون کے بنیادی تصورات، مقاصد شریعت اور اجتہاد، اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون، اسلام کا قانون جرم و سزا، اسلام کا قانون تجارت و مالیات، مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ، فقہ اسلامی دورجدید میں۔
محاضرات سیرت میں ان موضوعات کا ذکر ہے: مطالعہ سیرت کی ضرورت واہمیت، سیرت اور علوم سیرت، علم سیرت، مناہج فقہا، چند نامور سیرت نگار اور ان کے امتیازی خصائص، سیاست مدینہ: دستور اور نظام حکومت، سیاست مدینہ: معاشرت ومعیشت، کلامیات سیرت، فقہیات سیرت، مطالعہ سیرت پاک وہند میں، مطالعہ سیرت دور جدید میں، مطالعہ سیرت: مستقبل کی ممکنہ جہتیں۔ محاضرات عقیدہ وایمانیات غالباً زیر طباعت ہیں۔ یہ کل پانچ محاضرات ہیں۔ ان محاضرات میں بے شمار علمی ذخائر اور نایاب علمی موتی موجود ہیں۔ ڈاکٹر غازی ؒ کو فن تاریخ سے بہت لگاؤ اور دلچسپی تھی جس کا اندازہ ان محاضرات کو پڑھ کر لگایا جا سکتا ہے۔
ایک مقام پر ڈاکٹر غازیؒ لکھتے ہیں: ’’افسوس یہ ہے کہ ہمارا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ مغرب سے آنے والی ہر رطب و یابس تحریر کو تحقیق کا بے مثل نمونہ سمجھتا ہے۔ اس طبقے کے بارے میں حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے آج سے اسی نوے سال پیشتر فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ نہایت پست فطرت ہے۔ فطرت کی یہ پستی آج انتہاؤں کو چھوتی محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کے اثرات قرآن مجید، حدیث رسول، فقہ اسلامی اور سیرت پاک کے ذخائر پر عدم اعتماد کی صورتوں میں سامنے آنے لگے ہیں‘‘۔ والدین واساتذہ کرام کی اخلاقی تربیت اور دعاؤں کی برکت، دینی تعلیم ودینی حمیت وغیرت کا نتیجہ تھا کہ عصری علوم وفنون پر دسترس حاصل ہونے کے باوجود مرحوم میں مغرب سے مرعوبیت یاتجدد پسندی کی جھلک بالکل نہیں پائی جاتی تھی۔
آپ تحریک ختم نبوت کے داعی تھے۔ ختم نبوت کی تحریک میں عملی طور پر حصہ لیا۔ نومبر ۱۹۸۴ء میں کیپ ٹاؤن، (جنوبی افریقہ) میں قادیانیوں نے مسلمانوں کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا تو وہاں کے مسلمانوں کی فرمائش پر اس کیس کی پیروی کے لیے ایک وفد مسلمانوں کی مدد کے لیے گیا تھا۔ اس وفدمیں مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا عبدالرحیم اشعر، ڈاکٹر خالد محمود، مفتی محمد تقی عثمانی جیسے اکابرین امت شامل تھے۔ اس وفد میں آپ بھی شامل تھے۔ اس وفد نے مثالی خدمات انجام دیں۔ بالآخر وہاں کی عدالت نے اپنا حکم امتناعی واپس لے کر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔
ایک سائل نے آپ سے سوال کیا کہ کیا قادیانی حنفی یا شافعی کی طرح مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ یا مسلک ہے یا الگ مذہب ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا کہ ’’ شریعت کی روسے ہر منکر ختم نبوت اور مدعی نبوت اسلام کے دائرہ سے خارج ہے۔ یہ تو شریعت کی بات ہوئی۔ پاکستان کاقانون یہ ہے کہ ہمارے ہاں قومی اسمبلی کی متفقہ رائے سے ان کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے اور پاکستان میں ۱۹۴۷ء سے لے کر آ ج تک اتنے بڑے پیمانے پر اتفاق رائے کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی جب یہ ترمیم کر رہی تھی تو اس میں اس وقت ۱۰۰فی صد حاضری تھی۔ میں اس کا چشم دید گواہ ہوں ۔ سو فیصد ووٹ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حق میں ڈالے گئے۔ سینٹ میں بھی سو فیصد حاضری اور سو فیصد ووٹ تھا۔ کوئی ایک ووٹ بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ سب نے اتفاق رائے سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اس لیے آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ ایسا غیر مسلم گروہ حنفی شافعی کی طرح اسلامی مسلک کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے علاوہ بہت سے دوسرے ممالک بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ پاکستان سے بہت پہلے یہ فیصلہ متعدد دوسرے ممالک میں کیا جا چکا ہے۔ مصر میں ۱۹۳۵ء میں یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ سعودی عرب میں ۱۹۷۴ء کے اوائل میں یہ فیصلہ ہو اتھا۔ کئی اور ممالک میں ا س سے بھی پہلے فیصلہ ہو چکا تھا‘‘۔
اخلاص کسی پر تھوپا نہیں جاتا۔ محبت، اخلاص کا محض ایک عنصر ہے اور محبت کے متوالے سب اس کی کیفیات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ڈاکٹر غازیؒ اخلاص کے پیکر تھے۔ان سے فیض کے طالب ہر وقت فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ڈاکٹر صاحبؒ باوجود ابدی حیات کے ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ سوگواری کے عالم میں یہی کافی ہے کہ:
سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہو گئیں
خاک میں کیا صورتیں ہو ں گی کہ پنہاں ہو گئیں
مولانا محمد عرفان
(مدرسہ امام ابویوسف، شادمان ٹاؤن، کراچی)
( ۱۸ )
یوں تو میں نے اس عظیم ہستی کو ۲۸؍ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو بنوں کی فقہی کانفرنس میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا جہاں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے اصول الفقہ کی اہمیت پر موثر خطاب فرمایا تھا،لیکن کیا معلوم تھاکہ قسمت ساتھ دے گی اور مجھے اس عظیم ہستی سے شرف تلمذ بھی حاصل ہوگا۔ ۲۰۰۶ء کے اوائل میں ایل ایل بی شریعہ کے چھٹے سمسٹر میں جناب ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فقہ العلاقات الدولیۃ پڑھائی۔ اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوتی، انتہائی شفقت فرماتے۔ ایک دن ملاقات کے لیے گیا تو فرمانے لگے کہ بھئی، آج ہماری ترجمانی کرو گے۔ وہاں آپ کے دفتر میں ایک افغانی عالم (جن کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ مولانا عبد الباقی صاحب تھے) تشریف فرما تھے۔ وہ غازی صاحب کی بات تو سمجھ سکتے تھے، لیکن خود اردو بولنے سے قاصر تھے۔ موضوع بحث مولانا عبد الباقی صاحب کی تالیف ’’السیاسۃ والادارۃ الشرعیۃ فی ضوء ارشادات خیر البریۃ‘‘ کا اردو ترجمہ ’’اسلام کا نظام سیاست وحکومت‘‘ تھا۔ (یہ کتاب عربی اور فارسی میں بھی ترجمہ ہوئی ہے اور شنید ہے کہ وفاق المدارس العربیہ اس کو داخل نصاب کرنا چاہتا ہے۔) جناب غازی صاحب نے اس کتاب کے لیے تقدیم لکھنے کی ہامی بھری تھی۔
سید محبوب الرحمن
(متعلم ایل ایل ایم، شریعہ فیکلٹی،
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد)
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ فکر و نظر کے چند نمایاں پہلو
ڈاکٹر محمد غطریف شہباز ندوی
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا نام نامی تو خاصے عرصہ سے ذہن میں تھا اور عربی مدارس کے نظام ونصاب میں تبدیلی کے سلسلہ میں ان کے فکر انگیز خیالات بھی مطالعہ میں آئے تھے، لیکن با ضابطہ ان کی کسی تصنیف یا مجموعہ محاضرات کے مطالعہ کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ سرسری سی معلومات سے اتنا تو اندازہ تھا کہ فکرو نظر کے اعتبار سے موصوف کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیائے اسلام کی چند منتخب روزگار شخصیات میں سے ہوتا ہے۔ جب ان کی وفات (۲۶ستمبر،۲۰۱۰)کے بعد مؤقر مجلہ ’الشریعہ‘ کے مدیر شہیر جناب مولانا عمار خان ناصر صاحب کا دعوت نامہ موصول ہوا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی یاد میں الشریعہ کی اشاعت خصوصی کے لیے مضمون لکھوں تو راقم نے موصوف کی شخصیت اور کارناموں پر لکھنے کا عزم کرلیا اور اس مضمون کا ایک فوری فائدہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی کئی کتابیں خصوصاً محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث اور محاضرات فقہ بالاستیعاب پڑھنے کا موقع مل گیا۔ حاصل مطالعہ کے طور پر چند معروضات پیش خدمت ہیں:
سوانح زندگی:
ڈاکٹر محمود احمد غازی (فاروقی) ۱۳؍ ستمبر ۱۹۵۰ء کوکاندھلہ مظفرنگر(ہندوستان )میں پیدا ہوئے۔ (۱) ان کے والد محمد احمد فاروقی مولانا شیخ الحدیث محمدزکریاکاندہلوی کے خلیفہ تھے۔ (۲) خاندانی تعلق مولاناتھانوی سے تھا۔ اصلاً تووہ تھانہ بھون ضلع مظفرنگرکے رہنے والے تھے، مگران کی شادی کاندھلہ کے ایک بزرگ حکیم قمرالحسن کی دخترسے ہوئی جو کہ سابق امیرتبلیغ مولانا محمداظہارالحسن کاندھلویؒ کے بڑے بھائی تھے۔ اس رشتہ کے بعد وہ کاندھلہ جاکررہنے لگے تھے۔ جب محموداحمدغازی ۶، ۷ سال کے تھے تو یہ کنبہ کراچی چلاگیا جہاں محموداحمدکو بنوری ٹاؤن کے مدرسہ میں داخل کرایاگیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد انھوں نے مروجہ طرز پراسلامی علوم کی تحصیل شروع کی۔ اس طرح علامہ محمدیوسف بنوریؒ سے انہوں نے پڑھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے والد راولپنڈی منتقل ہوئے توانہوں نے وہاں کے مدرسہ تعلیم القرآن میں تعلیم جاری رکھی۔ ۱۹۶۲ء میں عربی کامل کا امتحان پاس کیا اور ۱۹۶۶ء میں درس نظامی کا پورا کورس مکمل کرلیا۔ ۱۹۷۲ء میں عربی زبان میں ایم اے کیا۔ اسی کے ساتھ فارسی اور فرنچ میں ڈگریاں حاصل کیں۔ انھوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی جس کا موضوع شاہ ولی اللہ سے متعلق تھا۔ (۳)
تدریسی خدمات :
تعلیم کی تکمیل کے بعدڈاکٹر غازی صاحب نے راولپندی کے مدرسہ فاروقیہ اور مدرسہ ملیہ میں پڑھا یا۔ اس کے بعد ادار ہ تحقیقات اسلامی میں یہ خدمت انجام دی، پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اسلام کے سیاسی فکر کے ارتقا پر لیکچر دیے ۔ اس کے بعد بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں برسوں تک تدریس کی جہاں وہ شریعہ فیکلٹی میں پروفیسر، ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اوریونی ورسٹی کے نائب صدر سے لے کر وائس چانسلر تک رہے۔ نیز قطر فاؤنڈیشن دوحہ میں بھی فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔
تدریس کے علاوہ ڈاکٹر غازی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چےئرمین شریعہ بورڈ ، تکافل پاکستان کراچی کے شریعہ سپروائزری کمیٹی کے چیئرمین، مذہبی امور کے وفاقی وزیر (اگست ۲۰۰۲) سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعہ ایلپیٹ بنچ کے جج (۱۹۹۹-۱۹۹۸) اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائرکٹر نیز اسی یونیورسٹی کی دعوۃ اکیڈمی کے ڈائرکٹر وغیرہ جیسے اہم اور ذمہ دارانہ مناصب پر فائز رہے۔ قومی سلامتی کونسل کا رکن بھی ان کو بنایا گیا ۔ اسی طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے نکلنے والے دو اہم علمی مجلات الدراسات الاسلامیہ (عربی)اور فکر ونظر (اردو) کاایڈیٹر بھی ان کومقررکیاگیا۔ اپنی علمی فکری اور عملی خدمات کے قومی اور بین الاقوامی سطح کے کتنے ہی اداروں کی ممبری، اور فقہی مشیر کی حیثیت سے بھی انھیں حاصل ہوئی جن میں پاکستان کے متعدد اداروں کے علاوہ ایران، شام، اسپین ، مصر اور سعودی عرب کے مؤقر و مقتدر ادارے شامل ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر غازی کی پوری زندگی عملی و علمی نشاط وسرگرمی سے عبارت تھی۔(۴)
علمی آثار:
اگر چہ ڈاکٹر غازی کی شہرت عام اور روایتی علما سے مختلف اور جدید اسلامی اسکالر و مفکر کے بطورزیادہ تھی، تاہم ان کی تقریریں وتحریر یں بتاتی ہیں کہ وہ راسخ العقیدہ اور متبحر عالم تھے۔ انھوں نے اسلامیات کے متعدد موضوعات پر تیس کے قریب کتابیں اور ۱۰۰ سے زیادہ مضامین ومقالات لکھے۔ ان میں بعض کتابیں در اصل ان کے محاضرات کے مجموعے ہیں جو انھوں نے ادارہ ’’الہدیٰ ‘‘کی فرمائش پر قرآن، حدیث، فقہ، سیرت اور شریعت پر دیے تھے۔ یہ تقریبا ۶۸ لیکچرز ہیں جن کو الگ الگ کتاب کی صورت میں پاکستان کے معروف ناشر ’’الفیصل‘‘ نے شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر غازی عربی ،اردو اور انگریزی میں لکھتے تھے۔ انھوں نے اردو سے عربی اور عربی سے اردو میں علمی اور اہم کتابوں کے کامیاب ترجمے بھی کیے ہیں ۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی تصنیف یا ترجمہ اور ایڈیٹنگ کی ہوئی۔ بارہ کتابیں غیر مطبوعہ ہیں۔ یہ کتابیں اردو ،عربی اور انگریزی میں ہیں اور ان میں بعض زیر طبع ہیں جن میں مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات کا عربی ترجمہ، اقبالؒ کے خطبات کا عربی ترجمہ، مقاصد شریعت، اسلام اور مغرب،ڈاکٹر محمد حمید اللہؒ کی سیرت نبوی پر فرنچ میں لکھی گئی کتاب کا انگریزی ترجمہ اور امام غزالیؒ کی کتاب قواعد العقائد کا انگریزی ترجمہ بھی شامل ہے۔ (۶)
ایک بہترین متکلم:
ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک بہترین متکلم اسلام ہیں۔ قرآن و حدیث ، فقہ، سیرت اورشریعت پانچوں علوم پر انھوں نے قارئین (حاضرین) کے سامنے اہم اور ادق مسائل کو نہایت، رواں اسلوب سہل و آسان زبان میں اس طرح بیان کردیا ہے کہ تمام باتیں ذہن نشین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خطبات بہاولپورمیں بھی یہی انداز واسلوب ہے۔ تاہم ڈاکٹرمحمدحمیداللہؒ کاامتیازایجازہے اور اصلاً کلیات اور اہم امور کا بیان ہے اور خاص کر مختلف علوم اسلامیہ کی تدوین کی تاریخ پر ترکیز ہے، جبکہ ڈاکٹر غازی نے اپنے خطبات میں پانچوں علوم میں سے ہر علم کے اہم و مہتم بالشان اور ضرورت کے تمام مباحث نہایت جامع وبلیغ انداز میں بیان کردیے ہیں اور دوران تقریر بالکل سامنے کی آسان مثالیں دے کر بحث کو بہت آسان کردیا ہے۔ عصر حاضر میں اسلامیات پر سہل الفہم اور مفید عام کتابیں لکھنے میں سب سے زیادہ شہرت مولانا سیدابو الاعلیٰ مودودی ؒ بانی جماعت اسلامی کو ملی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مباحث پر ڈاکٹر غازی نے سیدمودودیؒ کی متکلمانہ بحث و گفتگو کی یاد تازہ کردی ہے۔
علوم اسلامیہ کا استحضار:
ڈاکٹر غازی کے محاضرات کے سلسلہ کو پڑھنے سے پہلا تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ محاضر ومقرر کا علوم اسلامی کا گہرا استحضار ہے۔ یہ محاضرات انھوں نے ادارہ ’’الہدیٰ‘‘ کی مدرسات کے آگے دیے اور محض چند نوٹس کی مدد سے دیے۔ ان کے سامعین مدرسات تھیں جن میں ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی علمی صلاحیت کا ساتھ ہی متوسط درجہ کی صلاحیت رکھنے والی خواتین بھی ہوں گی۔ان کے سامنے امہات علوم اسلامیہ کی تفصیلات کا تعارف سلیس وسہل انداز میں پیش کرنا کارے دارد تھا،تاہم ڈاکٹر غازی اس مسئلہ سے نہایت عمدہ انداز میں عہدہ بر آ ہوئے۔محاضرات کے علاوہ بھی ان کی دوسری تحریروں میں بھی یہ صفت ظاہر ہے۔
راسخ العقیدہ عالم:
ڈاکٹر غازی اگر چہ متبحر عالم دین تھے مگر ان کی شہرت بطور ایک دانشور کے زیاد ہ تھی۔ ان کا حلقہ تعارف اور حلقۂ احباب میں بھی دانشور، اسکالرز، بین الاقوامی مسلم مشاہیر، چوٹی کے علما و مفکرین اور یونیورسٹی کے اساتذہ نیز حکومت کے ارباب حل وعقد زیادہ تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، وزیر برائے امور مذہبی تھے۔اپنی ان حیثیتوں کے ساتھ ہی وہ ایک راسخ العقیدہ عالم دین تھے۔ ان کے مطالعہ میں وسعت تھی اور ہر علم سے متعلق ان کی اپنی رائے تھی، لیکن ہر رائے قرآن وسنت کے مضبوط وپائدار دلائل پر مبنی ہے۔ تاہم ان کی بعض رایوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں:
’’ یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اورفلسفیانہ نوعیت کے یہ سوالات اٹھائے، وہ اصلاً محدثین تھے۔ مثال کے طورپر امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی کہ کلام الٰہی قدیم ہے کہ حادث ہے۔ یہ خالص عقلی اورفلسفیانہ مسئلہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ اٹھایاجو ایک محدث ہیں۔‘‘ (۷)
ڈاکٹرصاحب کی اس رائے سے اتفاق کرناذرامشکل ہے کیونکہ صورت حال اس کے برعکس تھی اوروہ یہ کہ مسلمانوں میں کلامی وفلسفیانہ نوعیت کے سوالات پہلے ہی سے اٹھ رہے تھے۔ ان کے محرک وہ یونانی علوم تھے جن کا ترجمہ بڑی شد ومد سے خلافت بنوامیہ کے اخیر اوربنوعباس کے آغاز میں ہورہاتھا۔اس کے علاوہ شعوبی، زندیقی، سبائی تحریکیں اوران سے متاثرفارسی ذہنیت کے نومسلم عناصرتھے۔ معتزلہ ومتکلمین نے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی۔جہاں تک محدثین کی بات ہے تو انہوں نے تومسلمان اہل علم کے کلام ومنطق اورفلسفہ یونانی میں اس انہماک کو غلط ہی سمجھا اوراس پر تنقیدکی۔ پھریہ کیسے کہاجاسکتا ہے کہ انہوں نے عقلی اورفلسفیانہ نوعیت کے سوالات سب سے پہلے اٹھائے ۔
مجتہدانہ سوچ کے مالک مفکر:
اعلیٰ درجہ کا تفکر اور تحقیقی نقطۂ نظرڈاکٹرصاحب کی ہر تحریر سے عیاں ہے۔ اس طرح وسعت مطالعہ اور مسلسل غور وفکر نے ان کی سوچ کو مجتہدانہ بنادیا تھا چنانچہ ایک عالمی فقہ کا تصور اور کسی ایک فقہ میں محصور نہ ہونا ان کی مجتہدانہ فکر کا غماز ہے۔ کا سمو پولیٹن فقہ کے ساتھ ہی حدیث کے بارے میں کہا کہ ’’علم حدیث میں ایک نیا پہلو ایسا ہے جو اس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے‘ ‘اور ’’نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج کے دورکے تہذیبی، تمدنی، سیاسی، معاشی، اجتماعی، اخلاقی اورروحانی ضروریات کے مطابق ابواب کی ترتیب اورمضامین کی تقسیم کی جائے اوریوں مجموعے مرتب کیے جائیں۔‘‘ (۸)۔ کتاب کے آخر میں انھوں نے حدیث پر نئے سرے سے کرنے کے کام سمجھائے اور مثالوں سے ان کی وضاحت کی۔ تدریس قرآن کے سلسلہ میں جدید تقاضوں پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ’’صحابہ کرام نے کسی فقہی، کلامی یا تفصیلی معاملہ کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی۔ دعوت صرف دین کی دی جاتی تھی۔ دعوت شریعت یا دعوت فقہ کبھی نہیں ہوتی تھی‘‘ (۹)۔ اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اسلام میں ریاست وحکومت تو براہ راست مطلوب نہیں ہے، لیکن ایک اسلامی معاشرہ اورامت مسلمہ کا قیام یقیناایک دینی فریضہ اورراست مطلوب شرعی ہے۔ (۱۰) انہوں نے مشہورمستشرق ڈاکٹر اسپرنگرکے حوالے سے یہ فکرانگیز خیال بھی ظاہرکیاکہ علم حدیث اورعلم اصول فقہ یہ دونوں اسلام کی ذہانت (geniusness) کازبردست اظہارہیں۔ ان کے الفاظ میں ’’مسلمانوں میں creative Genius کاسب سے اعلیٰ نمونہ علم اصول الفقہ ہے۔ علم حدیث مسلمانوں کی Accumulative Genius کا بے مثال نمونہ ہے۔‘‘ (۱۱)
وسعت نظری و رواداری:
ڈاکٹر صاحب ان چنیدہ صاحبان دانش میں سے ہیں جن کا مطالعہ متنوع اور وسیع ہے۔ وہ زیادہ تر عربی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ (۱۲) فرنچ جاننے کی وجہ سے ان کے مطالعہ میں مزید وسعت پیدا ہوگئی، خاص کر مستشرقین کی تحریریں راست ان کے مطالعہ میں آئیں۔ وسعت مطالعہ اور تفکر سے وسعت نظری پیدا ہوتی ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں وسعت نظری اور رواداری پیدا ہوگئی۔ وہ حنفی تھے لیکن متشدد وکٹر قسم کے حنفی نہیں۔ان سے سوال کیاگیاکہ کیاحنفی کی نماز شافعی کے پیچھے ہوجائے گی،بعض لوگ منع کرتے ہیں۔اس سوا ل کے جواب میں وہ کہتے ہیں:
’’فقہ اسلامی میں ایساکوئی حکم موجود نہیں ہے۔ جس نے بھی ایسا کہا، فضول بات کی ہے اوربالکل غلط کہی ہے۔ جس مسلک کا امام نماز پڑھا رہا ہو، آپ بے تکلف وبے تردد اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اگرآج امام شافعی یہاں تشریف لے آئیں تو میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے نہیں دوں گا۔ خود بھی امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور دوسروں سے بھی کہوں گا کہ امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھیں۔‘‘ (۱۳)
اسی طرح وہ سنی تھے، راسخ العقیدہ سنی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ پی ایچ ڈی کے مقالہ میں ان کے ایک ایرانی ممتحن نے منفی رپورٹ لکھی تھی۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف کافی حدتک مسلکی رواداری کا اظہار کرتے تھے بلکہ فقہ جعفری کے مطالعہ کا مشورہ بھی دیتے تھے۔ شیعوں کی تکفیرکے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:
’’یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہییں۔ یہ دنیائے اسلام میں ایک ٹائم بم رکھنے کے مترادف ہے۔ شیعہ حضرات آج سے نہیں ہیں، کم سے کم تیرہ سو برس سے چلے آرہے ہیں۔ کبھی بھی مسلمانوں نے ان کو کافر نہیں کہا۔بڑے بڑے اہل علم نے شیعہ عقائد کا مطالعہ کیا تو ان کو غلط تو کہا، ان پر تنقید تو کی اور ان کمزوریاں واضح کیں، لیکن کسی یہ نہیں کہا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہٰذا یہ بات جو پچھلے پندرہ بیس سالوں سے پیداہوگئی ہے، اس نے دنیاے اسلام میں بڑافساد پیدا کیا ہے۔ میرے نزدیک شیعوں کے عقائد غلط ہیں، اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ بس، بات ختم ہوگئی۔‘‘ (۱۴)
معتدل فکرو اسلوب:
وسعت نظری اور جامعیت سے فکر میں اعتدال پیدا ہوا۔ الہدیٰ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے تحت خواتین قرآن و حدیث کے دروس کا اہتمام کرتی ہیں۔ ان پر بعض علما نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں کہتے ہیں :
’’بعض علماے کرام کے بارے میں، میں نے سنا ہے کہ ان کہناہے کہ تدریس قرآن کے لیے پہلے مدرسہ کا دس سالہ نصاب مکمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی تدریس قرآن میں مصروف ہونا چاہیے ۔۔۔میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو نہ بنیادکی ضرورت ہے نہ بے ساکھیوں کی۔ قرآن مجید خود بنیادفراہم کرتاہے، دیواریں بھی اورتعلیم کی بھی تکمیل کر دیتا ہے۔‘‘ (۱۵)
اسی طرح یہ اعتدال ان کے اسلوب تقریر وتحریر سے بھی مترشح ہوتا ہے۔ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بھی نہایت انکساری سے کہتے ہیں: ’’میری رائے یہ ہے، ہوسکتا ہے غلط ہو‘‘۔ اسی طرح کسی شخص یا فکر کی تردید میں بھی اسلوب کا دھیماپن صاف نظر آتا ہے۔ شدت، تعصب اور تعلی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتی، البتہ ان کے لب ولہجہ سے علمی اعتماد ضرور ٹپکتا ہے۔ انھوں نے انصاف پسندی کا ثبوت دیا ہے کہ مستشرقین پر تنقیدیں بھی کی ہیں تو ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ (۱۶) چہرے کے پردے کے بارے میں معتدل رائے کا اظہار کیا ہے۔ (۱۷)
متحرک وفعال زندگی :
ڈاکٹر صاحب موصوف نے صرف ساٹھ سال کی عمر پائی اور علمی حیثیت سے نہایت اعلیٰ اور بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچے۔ انھوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرر کھی تھی۔ چنانچہ علمی میدان میں اور وزارت نیز جج کے اعلیٰ عہدوں پر رہ کربھی اسلام کی خدمت کی اور دانشوری کی روایت میں ایک گوہر نایاب بن کر چمکے۔ اپنی اعلیٰ حیثیت میں انھوں نے ۱۰۰ سے زیادہ قومی و بین الاقوامی کانفرنسوں ومذاکروں میں شرکت کی اور پچاسوں ممالک کے سفر بھی کیے۔ ۱۹۸۷ سے ۱۹۹۴ تک اسلام آباد کی فیصل مسجد کے خطیب اوراسلامی سینٹرواقع فیصل مسجد کے ڈائرکٹر کے فرائض انجام دیے۔ اسی طرح نیشنل ہجرہ کونسل کے عالمی مشاورتی بورڈ کے ممبر رہے۔ (۱۸) طالب علمی کے دوران ان کا تعلق پاکستان کی معروف طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی رہا جس کا فکری رشتہ جماعت اسلامی سے ہے۔ ۱۹۸۴ میں وہ اس کمیٹی کے رکن مقرر ہوئے جس نے پاکستان میں اہانت رسول کی سزاکا تعین کیا۔ وہ کچھ عرصہ جنرل ضیاء الحق کے عربی مترجم بھی رہے۔اس کے علاوہ التجمع العالمی للعلماء المسلمین(مکہ مکرمہ) کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر نیز علامہ یوسف القرضاوی کی قیادت میں الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین (قاہرہ مصر)کے رکن اوراسی طرح ادارہ مجمع التقریب بین المذاہب الاسلامیہ ایران کے رکن تھے۔ (۱۹)
جدید موضوعات:
علوم اسلامیہ قرآن، حدیث، فقہ وسیرت تو ان کے مطالعہ کی جولان گاہ تھے ہی، انھوں نے بالکل جدید موضوعات پر بھی قلم اٹھایا،چنانچہ گلوبلائزیشن پر عربی میں العولمۃ کے نام سے کتاب لکھی جو بیروت سے شائع ہوئی۔ انہوں نے مجدد الف ثانیؒ اور اقبالؒ کا بھی خاصا کام عربی میں کیا۔ اقبال کے خطبات اور ان کی شاعری کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح ’’الحرکۃ المجددیہ‘‘ کے نام سے کتاب لکھی اور مجدد ؒ صاحب کے متعدد خطوط کا بھی عربی میں ترجمہ کیا۔ برصغیر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے ساتھ ہی افریقہ کی ایک اہم تحریک ’’السنوسیہ‘‘ کا تعارف بھی کرایا۔ انھوں نے اسلام کے قانون بین الاقوام اور اسلامک انٹر نیشنل لا پر کتابیں لکھیں اور اسلام میں ریاست اور قانون سازی کا تعارف کرایا۔ موجودہ زمانہ میں خلافت کے تصور کو کسی طرح عملاً برتا جاسکتا ہے، اس کا نقشہ بھی انھوں نے پیش کیا اور اس طرح اسلام کے سیاسی فکر میں اضافہ کیا۔
عالمی فقہ کا تصور:
بیسویں صدی علوم اسلامی کی نشاۃ ثانیہ کی صدی ہے۔ اس میں حدیث، تفسیر اور فقہ پر نئے انداز و اسلوب میں زبردست کام ہوئے ہیں۔ خاص کر عالم عرب میں مختلف اسلامی ممالک نے اس سلسلہ میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور نئی فقہ وجود پذیر ہونے لگی جس کا دائرہ ابھی فقہ کے ماہرین، اسکالروں اور طلبہ تک محدود ہے۔ عوام تک اس کے اثرات ابھی منتقل ہونے شروع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر غازی لکھتے ہیں:
’’دنیائے اسلام کے لوگوں نے ایک دوسرے سے استفادہ شروع کیا۔ ایران کے تجربات سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان سے سوڈان نے استفادہ کیا۔ سعودی عرب سے مصر نے استفادہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہی مسالک کی جو حدود تھیں، وہ ایک ایک کرکے دھندلانے لگیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا ے اسلام میں باہمی مشاورت اور اشتراک عمل سے یہ اجتہادی کام کیا جارہا ہے۔ اسی اجتماعی اجتہاد کے نتیجہ میں فقہی مسالک کی حدود مٹ رہی ہیں۔ ایک نئی فقہ وجود میں آرہی ہے جس کو نہ حنفی فقہ کہ سکتے ہیں نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ جعفری بلکہ اس کواسلامی فقہ ہی کہا جائے گا۔ میں اس کے لیے Cosmopolitan Fiqh یعنی عالمی یا ہر دیسی فقہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں۔‘‘ (۲۰)
اس کے بعد انھوں نے بینکاری اور مالیاتی اور بین الاقوامی تجارت و کاروبار کے حوالہ سے اپنے اس تصور کی مزید وضاحت کی ہے۔ ۱۹۸۰ء میں بینکاری کے اسلامی نظام کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور کوئی مسلک نہ رکھنے والے سب علما متفقہ طور پر شریک ہوئے تھے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ:
’’ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ محض فقہ حنفی کی بنیاد پر نہیں ہے اور نہ اس دستاویز کو فقہ حنفی کے لٹریچرکا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہاجاسکتا ہے کہ فقہ شافعی کی بنیاد پر تیار ہوئی ہے۔ یہ فقہ زیدی یا فقہ جعفری کی بنیاد پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے تمام فقہا اور تما م فقہی مسالک کے ماننے والوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کا عربی، ملائی ، بنگلہ اور اردو وغیر میں ترجمہ ہوا اور دنیا میں ہر جگہ اس سے استفادہ کیا گیا‘‘۔ (۲۱)
اس طرح کی اور بھی مثالیں انھوں نے دی ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ’’موجودہ حالات میں کسی متعین فقہی مسلک کی پابندی پبلک کی حد تک بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف فقہوں میں بعض ایسے اجتہادات ہوتے ہیں جو آج کے دور میں مشکل معلوم ہوتے ہیں۔‘‘ (۲۲)
عصر جدید کے جو پیچیدہ مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے بعض اوقات عدم تقلید اور اجتہادی صلاحیت سے کام لینا ناگزیز ہوجاتا ہے، تاہم یہ ہے انتہائی نازک اور احتیاط کا متقاضی کام اور ہر شخص کو اس کی کھلی چھوٹ نہیں دی جاسکتی ۔ اس نزاکت کاادراک ڈاکٹر صاحب کو بخوبی ہے۔ وہ کہتے ہیں:
’’ یہ اتنے بڑے اور پیچیدہ مسائل ہیں کہ کسی ایک فقہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کاحل تلاش کرنا مشکل ہے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ چار مشہور فقہی مسلکوں کے دائرے سے نکل کر دیکھنا پڑا۔ بعض جگہ براہ راست قرآن وسنت کی نصوص سے استنباط کرکے تمام فقہا یا زیادہ تر فقہا کے نقطۂ نظر کو نظر انداز کرنا پڑا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں کہ ہر کس وناکس اس کا بیڑا اٹھا سکے۔‘‘ (۲۳)
ظاہر ہے کہ ایسے مقامات پر اجتماعی اجتہاد تفصیلی غور و خوض، احساس ذمہ داری، تقویٰ و خدا ترسی اور از حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ تبھی ممکن ہے کہ امت کو فقہی انار کی یا فتوے بازی کی انار کی سے نکلا جاسکے، جیسا کہ بد قسمتی سے برصغیر میں یہ .فضا بنی ہوئی ہے۔
دوبڑے چیلنج :
ڈاکٹر غازی کے نزدیک آج کے دو بڑے چیلنج ہیں: ایک چیلنج ملٹی نیشنل کمپنیوں اورمالیاتی اداروں کا ہے جس کا جواب مسلمان تیار کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ دوسراچیلنج میڈیاکا چیلنج ہے۔ میڈیاکی یلغاراتنی تیزی، شدت اور سرعت سے ہو رہی ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کرآپ دنیاکے دو ڈھائی سو چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ توقع کرنا یایہ مطالبہ کرناکہ یہ چینل بند کیے جائیں اوران کو ختم کیاجائے، ایک غیرحقیقت پسندانہ مطالبہ ہے۔ آج سے پچاس برس پہلے یہ بات ممکن تھی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اوردنیاکے ہرفتنہ سے اوردین وتہذیب پر اثراندازہونے والی ہر چیز سے محفوظ ہوجائیں۔یہ تو کوئی جواب نہیں کہ آپ اپنے گھرمیں تالا لگا دیں اور پردہ ڈال کر بیٹھ جائیں۔ سیلاب پردے ڈالنے سے نہیں رکتا، تالے ڈالنے سے نہیں رکتا۔ یہ دوسراچیلنج ہے جس کا جواب دینا ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں میں جو میڈیا کے ماہرین ہیں، ان کو اس سلسلہ میں غوروخوض کرناچاہیے۔
ایک اہم فکری نکتہ:
بیسویں صدی میں ایک نیاظاہرہ (phenomenon) دین کی سیاسی تعبیرکا پیش آیا۔ بعض مسلم مفکرین اور مصنفین کے ہاں سیاست پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اس کے بعض خارجی اسباب ہیں، اس کے کچھ مثبت پہلوبھی ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹرغازی نے اپنی رائے یوں دی ہے جس میں سبب، مثبت پہلوپرتبصرہ کے ساتھ ہی انہوں ایک گونہ اس پر نظرثانی کی دعوت بھی دی ہے:
’’سو ڈیڑھ سو سال پہلے تک ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگوں کی زندگی میں بنیادی کردار ریاست کا ہوا کرتا تھا۔ ریاست نظریہ کی علمبرداراورمحافظ ہوتی تھی، ریاست نظریہ کو فروغ دینے کا کام کرتی تھی۔ کمیونسٹ ریاست بنی، اس نے کمیونسٹ نظریہ کو فروغ دیا۔۔۔اس زمانہ کے مسلم مفکرین کو خیال آیاکہ جس طرح مغربی ریاستیں اپنے نظریات کو پھیلارہی ہیں، اسی طرح اگرایک بڑی مضبوط اسلامی ریاست قائم کی جائے جواسلامی نظریات کو پھیلائے اور ان کو فروغ دینے کا کام کرے تو اسلامی نظریات کو بھی اسی طرح فروغ حاصل ہوجائے گا۔اس تصور کے پیش نظر بیسویں صدی کے مفکرین اسلام کے نزدیک اسلامی ریاست کو بہت اہمیت حاصل ہوگئی اوراحیاے اسلام کے عمل میں اسلامی ریاست کا قیام بنیادی حیثیت کا حامل قرار پاگیا۔ ریاست ان کی فکر کا اصل اورمرکزی نکتہ بن گئی، ان کی ساری توجہ اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز ہوگئی ۔۔۔ لیکن اس فکر کا ایک مثبت فائدہ یہ ہواکہ اسلامی ریاست کے بارے میں بہت سا علمی اورتحقیقی کام سامنے آگیا۔۔۔ دوسری طرف دنیا میں یہ ہواکہ ریاست کی مرکزیت ختم ہوگئی۔ سویت یونین کو زوال آگیا۔ کمیونزم ایک نظریہ کے طورپر دنیاسے ختم ہوگیا۔۔۔اب جو ادارے اپنے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اوربڑے بڑے بینک ہیں۔ ورلڈ بینک اورآئی ایم ایف وہ ادارے ہیں جو غیرریاستی ادارے ہیں، لیکن مالیات اورتجارت ان کے ہاتھ میں ہے۔اس وقت دنیاکے مستقبل کو بنانے اوربگاڑنے کا یادنیائے اسلام کو کنٹرول میں کرنے کاجوسب سے بڑاذریعہ ہیں، وہ یہ ملٹی نیشنل ادارے اورکارپوریشنز ہیں ۔ان کے پاس دنیاکی معاشی زندگی کی لگامیں ہیں، ان کے پاس دنیاکے معاشی وسائل اورمالیاتی خزانوں کی کنجیاں ہیں۔۔۔ اس لیے بظاہر ایسامعلوم ہوتاہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ریاست کا کرداربنیادی نہیں ہوگا، بلکہ ان اداروں کا کرداربنیادی ہوگا۔‘‘(۲۴)
خاکسار راقم یہ سمجھتا ہے کہ سیاسی اسلام کے نمائندوں کو اس رائے پر، جوان کے کسی ناقد کی طرف سے نہیں بلکہ ہمدردکی طرف سے آئی ہے، ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔
مصادرومراجع:
(۱) سید منصورآغا ، جدید خبر اردوروزنامہ، نئی دہلی بھارت، ۲۸ ستمبر ۲۰۱۰ء
(۲) ایضاً (۳) ایضاً (۴) یہ معلومات انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں ۔ (۵) ایضاً (۶) ایضاً
(۷) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر، محاضرات حدیث، الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع دوم دسمبر ۲۰۰۵ صفحہ ۶۹
(۸) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر، محاضرات حدیث، الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع دوم دسمبر ۲۰۰۵ صفحہ۴۵۷
(۹) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر، محاضرات قرآنی، الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع جولائی ۲۰۰۴ صفحہ ۳۸۲
(۱۰) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر،محاضرات فقہ الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع جون ۲۰۰۵ صفحہ ۱۷۰
(۱۱) محاضرات حدیث صفحہ ۲۸۔ نیز محاضرات فقہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں: بعض جدید مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی عقلی منہاجیات یعنی intellectual methodology جس فن میں سب سے زیادہ نمایاں ہوکرسامنے آتی ہے وہ، علم اصول فقہ ہے۔ دیکھیے صفحہ ۶۰
(۱۲) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر،محاضرات حدیث، الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع دوم دسمبر ۲۰۰۵ صفحہ ۹۰
(۱۳) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر،محاضرات فقہ، الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع جون ۲۰۰۵ ص ۵۱۰
(۱۴) ایضاً (۱۵) محاضرات قرآنی، صفحہ ۴۳
(۱۶) لکھتے ہیں: ’’تیسرانقطۂ نظر یہ ہے جو مجھے بھی ذاتی دلائل وغیرہ کو دیکھ کردرست معلوم ہوتاہے۔ وہ یہ کہ چہرہ کا ڈھکنا توافضل اورعزیمت ہے، لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔‘‘ دیکھیں محاضرات حدیث صفحہ ۴۶۴۔
(۱۷) ملاحظہ ہو ،محاضرات حدیث صفحہ۴۴۳۔
(۱۸) انٹرنیٹ سے (۱۹) انٹرنیٹ سے
(۲۰) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر،محاضرات فقہ الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع جون ۲۰۰۵ صفحہ ۵۳۴
(۲۱) محمود احمد غازی ،ڈاکٹر،محاضرات فقہ الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع جون ۲۰۰۵ صفحہ ۵۳۴
(۲۲) ایضاً صفحہ ۵۳۵ (۲۳) ایضاً، صفحہ ۳۸ (۲۴) ایضاً، محاضرات فقہ صفحہ ۵۴۳
ڈاکٹر غازی مرحوم ۔ فکر و نظر کے چند گوشے
ڈاکٹر محمد شہباز منج
تحمل، برداشت، محبت، وسیع النظری، بلند نگہی، شیریں بیانی، جذب دروں، خوداعتمادی، علم کی گہرائی و گیرائی، اپنے علمی وتہذیبی ورثے پر فخر اور دوسروں میں یہ فخر پیدا کر دینے کا ہنر، ایسا شخص آج کی اس خانماں خراب ملتِ اسلامیہ میں، خداوندِ قدوس کی نعمتِ عظمی ہی تو تھا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ عصر حاضر کے تہذیبی مزاج و نفسیات کے تناظر میں اہل اسلام کی رہنمائی اور امت کو درپیش جدید اندرونی و بیرونی اور فکری و تہذیبی چیلنجز کے مقابلہ کے لیے مطلوب اعلیٰ وژن اور اپروچ اور پختگی و ثقاہتِ علم وفکر کے حامل تھے۔ امت مرحومہ کو آج ایسے ہی مردانِ کار چاہییں مگر افسوس کہ یہ ڈھونڈے نہیں ملتے۔ ڈاکٹر غازی مرحوم کی رحلت سے محاورۃً نہیں واقعتا ایک غیر معمولی خلا پیدا ہو گیا ہے۔
و ماکان قیس ھلکہ ھلک واحد
ولکنہ بنیان قوم تھدما
’’قیس کامرنا ایک فرد کا مرنا نہیں، پوری قوم کی بنیاد کا منہدم ہو جانا ہے۔‘‘
ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر غازی ایسے لوگوں کوخراج تحسین تو پیش کرتے ہیں لیکن ان کے وژن اور فکر سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔حالانکہ ایسے بڑے لوگوں کو بہترین خراج تحسین یہ ہوتا ہے کہ ان کے افکار سے رہنمائی حاصل کر کے ان کے آدرشوں کی تکمیل کی کوشش کی جائے۔ میں یہاں ڈاکٹر صاحب کی فکر کے چند گوشوں کو سامنے لاکرملت کی تقدیربدلنے کی خواہش رکھنے والوں اور اسلام اور عالم اسلام کے بہی خواہوں کواس سے رہنمائی حاصل کرکے ڈاکٹر صاحب کے خوابوں کو شرمندۂ تعبیر کرنے کی اپنی سی کوشش کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔
کتاب وسنت سے گہرے ربط اور ان بحر ہاے معانی میں غواصی کی ضرورت
ڈاکٹر غازی فرماتے ہیں:
’’ہمارااللہ کی کتاب اور اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رابطہ سطحی اور رسمی سا رہ گیا ہے۔اسی لیے یہ ہم پر اپنے دروازے وا نہیں کرتے۔قرآن سے گہرے ربط کے لیے ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اقبالؒ کے توسط سے جو طریقہ بتایا ہے، وہ نوجوانان ملت کے لیے قابل تقلید ہے۔کہتے ہیں:علامہ ؒ نے لکھا ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں میرا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعدروزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا۔ایک روز تلاوت میں مشغول تھاکہ والد گرامی پاس سے گذرے اور فرمانے لگے : کیا کر رہے ہو؟میں نے عرض کیا : قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔وہ خاموش رہے اور چلے گئے۔اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا۔یہ معاملہ کئی دن رہا ۔ایک دن میں نے عرض کیا:آپ روزانہ پوچھتے ہیں حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔فرمانے لگے:دیکھو! جب تم کلام پاک پڑھا کروتو اس شعور واحساس سے کے ساتھ پڑھا کروکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تمہی سے ہم کلام ہے۔
ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف‘‘
(محاضرات قرآنی،ص۳۹)
کتاب اللہ سے ربط پیدا کرکے اس لامتناہی سمندر سے گوہر ہائے معانی نکالنے کے کتنے وسیع امکانات ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ، ڈاکٹرحمیداللہ مرحوم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ۔ڈاکٹر حمیداللہ نے، جیسا کہ وہ اپنے پاس قبولِ اسلام کے لیے آنے والے ہر شخص سے پوچھا کرتے تھے، اُس سے سوال کیاکہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا؟اس نے کہا:میں فرانسیسی دنیا کا سب سے بڑا اورمقبول موسیقار ہوں۔آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت پر جانے کا موقع ملا۔وہاں موجود لوگ ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔مجھے وہ دنیائے موسیقی کی سب سے اونچی چیز محسوس ہوئی۔میری ایجاد کردہ دھنوں اور ان کے نشیب وفراز سے بھی بہت آگے کی چیز،جہاں تک پہنچنے کے لیے دنیائے موسیقی کو ابھی بہت وقت درکار ہے۔میں حیران تھا کہ آخر یہ موسیقی اوراس کی دھنیں کس نے ترتیب دیں؟میں نے لوگوں سے بار باراس سے متعلق پو چھنا چاہا لیکن انہوں نے ہر بار مجھے اشارہ سے خاموش کر دیا۔ڈاکٹر حمیداللہ فرماتے ہیں کہ اس دوران وہ موسیقی کی بعض اصطلاحات بھی استعمال کر رہا تھا ،جن سے میں واقف نہ تھا۔جب وہ موسیقی بند ہو گئی تواس کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ موسیقی نہیں ،قرآن حکیم کی تلاوت تھی ۔ فلاں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اور موسیقی کی تو وہ ابجد سے بھی واقف نہیں۔لیکن اس کو یقین نہ آیا ۔اس کا کہنا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھنیں کسی کی بنائی ہوئی نہ ہوں ۔اسے سمجھایا گیا کہ یہ فن تجوید وقرأت ہے۔وہ کہنے لگا :یہ فن کب ایجاد ہوا ؟ اسے بتایا گیا کہ چودہ سو سال پہلے حضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسے ہی قرآن سکھایا تھا۔اس پر وہ گویا ہوا:اگر ایسے ہی ہے تو پھر بلاشبہ یہ اللہ کی کتاب ہے ۔پھر اس نے کئی جگہوں پر جاکر اور کئی قاریوں کی تلاوت سنی اور اب قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین حاصل کر کے مسلمان ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے سامنے تھا۔
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کرلیااور پیرس میں زیر تعلیم ایک الجزائری مسلمان کو اس کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کردیا۔کچھ عرصہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے۔الجزائری معلم نے بتایا کہ یہ قرآ ن سے متعلق کچھ شک کا اظہار کر رہا ہے۔میں نے سوچا کہ یہ جس بنیاد پر مسلمان ہوا تھا وہ بنیاد ہی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لہٰذا اس کے شک کا میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن اللہ کے بھروسے پر میں نے پوچھا :بتاؤ کیا مسئلہ ہے ؟وہ موسیقار بولا:معلم صاحب نے مجھے سورہ نصر پڑھائی ہے ۔اس میں افواجا اور فسبح کے درمیان خلا ہے ۔معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی چیز حذف ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں :ایک لمحے کو میرے پاؤ ں تلے سے زمین نکل گئی۔ دنیاے اسلام پر نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو فن تجوید اور موسیقی دونوں کا ماہر ہو اور اس کا شک دور کر سکے۔ میں چند سیکنڈ شش و پنج میں رہا، پھر اچانک اللہ نے میرے ذہن میں ایک پرانی بات ڈالی ۔بچپن میں جب مکتب میں قرآن پڑھا کرتا تھا، تو میرے معلم نے مجھے بتایا تھا کہ افواجا پر وقف نہیں کرنا بلکہ آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ایک مرتبہ میں نے افواجا پر وقف کیا تھا تو انہوں نے مجھے سزا بھی دی تھی ۔میں نے سوچا شاید اسی بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے۔میں نے اس سے کہا کہ آپ کے معلم تجوید کے اتنے ماہر نہیں ہیں۔دراصل یہاں لفظ افواجا کو غنہ کے ساتھ فسبح سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑا اور مجھے گود میں لے کر کمرے میں ناچنے لگااور کہا کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے ۔یہ سن کر میں نے اسے ایک اور قاری کے سپرد کر دیا ۔وہ وقتاً فوقتاً مجھ ملتا اور بہت سر دھنتا کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے۔وہ ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب زند گی گزار کر ۱۹۷۰ء میں فوت ہوا۔ (محاضرات قرآنی۔ص۲۲۷۔۲۳۰)
قرآن کی اسی معجز نمائی کے حوالے سے ڈاکٹر غازی مرحوم نے فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر موریس بکائی کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ڈاکٹر بکائی نے اپنے قرآن کی حقانیت پر ایمان لانے سے متعلق اپنے تاثرات بذات خود ان سے بیان کیے۔ نامور ہارٹ اسپیشلسٹ اور فرانس کی میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدرکے طور پر فرائض سرانجام دینے والے ڈاکٹر بکائی سعودی عرب کے شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے ۔انہیں وقتاً فوقتاً ریاض جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکاری مہمان کے طور ریاض میں ایک ہوٹل میں قیام پذیرتھے۔ان کے کمرے میں انگریزی ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کا ایک نسخہ پڑا ہوا تھا۔ شاہ سے ملاقات کا انتظار تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لیے اس نسخہ قرآنی کی ورق گردانی شروع کر دی۔اس سے پہلے عام عیسائیوں کی طرح انہیں بھی قرآن کو پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس ورق گردانی کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ قرآن میں بعض بیانات سائنسی نوعیت کے بھی ہیں۔ایک سائنسدان اور میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ناطے انہیں یہ بیانات دلچسپ لگے۔انہوں نے قرآن کو باربار پڑھا اور ایسے بیانات نوٹ کر لیے۔ انہیں خیال آیاکہ اگر ایسے ہی بعض بیانا ت بائبل میں بھی ہوں اورسائنس کی روشنی میں قرآن اور بائبل کے بیانات کا تقابل کیا جائے تو ایک دلچسپ سٹڈ ی سامنے آسکتی ہے۔پیرس واپس جاکر انہوں نے بائبل سے بھی اس نوعیت کے بیانات نوٹ کر لیے ۔اب دونوں کاتقابلی مطالعہ شروع کیا۔ عیسائی ہونے کی بنا پر قرآن سے انہیں کسی نوع کی عقیدت نہ تھی۔معروضی مطالعہ کی روشنی میں وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ قرآن کے سائنسی نوعیت کے تمام بیانات سو فیصد درست جبکہ بائبل کے بہت سے بیانات غلط تھے۔ ان کی یہ تحقیقی کاوش The Bible, The Quran and Science کے نام سے سامنے آئی،جس کا دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن کی حقانیت کے اس تجربی ثبوت نے ان کو اسلام کی صداقت کو ماننے پرآماد ہ کیا اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ (محاضرات حدیث،ص۴۴۹۔۴۵۰، محاضرات قرآنی،ص۴۳۔۴۴)
یہ اور اس طرح کے دیگر دلچسپ واقعات کے تذکرہ سے ڈاکٹر غازی مرحوم کا مقصود صاحبان فکر ونظر کے لیے قرآن کے بحر ناپیدا کنار میں غواصی کی تحریک و تشویق پیدا کرنا تھاکہ
صد جہانِ تازہ در آیات او ست
عصرہا پیچیدہ در آیات او ست
قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کے اندر بھی معانی ومفاہیم اور امکانات کی کئی دنیائیں آباد ہیں ۔ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے بھی بہت دلچسپ حقائق بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ سائنس کے طالب علموں اور جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہوگا ۔یہ واقعہ بھی ڈاکٹر صاحب مرحوم نے ڈاکٹر حمیداللہؒ سے روایت کیا ہے۔ڈاکٹر موریس بکائی نے بخاری ؒ کی سو احادیث منتخب کرکے ان کا جدیدسائنسی تحقیق کی روشنی میں جائزہ لیا۔اس جائزہ پر مبنی مقالہ شائع کرنے سے قبل وہ ڈاکٹر حمیداللہ کے پاس لائے۔انہوں نے دیکھا کہ منتخب کردہ احادیث کے سو بیانات میں سے اٹھانوے کو تو ڈاکٹر بکائی نے درست قرار دیا تھا ،لیکن دو کوغلط بتایا تھا۔ان دو بیانات میں سے ایک یہ تھا کہ جب کھانے میں کوئی مکھی گر جائے تو اس کو پورا اندر ڈبو کر نکال لو کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفاہوتی ہے ۔جب وہ گرتی ہے تو بیماری والاحصہ کھانے میں پہلے ڈالتی ہے،تم دوسرا پر بھی ڈبو لو تا کہ شفا والا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ مکھی کے کسی پر میں شفا نہیں ہوتی، وہ تو گندی چیز ہے ۔دوسر ی بات جو بکائی کے نزدیک غلط تھی، وہ یہ تھی کہ بنی عرینہ کے لوگوں کومدینہ میں آکر ایک بیماری لگ گئی ۔اس بیماری سے ان کے رنگ زرد ہو گئے،پیٹ پھول گئے اور ایک خاص انداز کابخارگویازردبخار ہو گیا۔حضورؐ نے ان سے فرمایا:تم مدینے سے باہر فلاں جگہ چلے جاؤ۔وہاں رہو اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ڈاکٹر بکائی کا موقف تھا کہ پیشاب تو جسم کا Refuse ہے ،اس سے علاج کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر بکائی سے کہا:میں سائنسدان تو نہیں ہوں، البتہ ایک عام آدمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں، اگر آپ وہ دور کردیں تو پھر بے شک اپنی اس تحقیق کو اپنے اعتراضات کے ساتھ شائع کر دیں۔ ایک یہ کہ سائنسدان جب تجربات کرتے ہیں تو ایک تجربے کے دوبار صحیح ثابت ہونے پر اسے پچاس فیصد درجہ دیتے ہیں، تین چار مرتبہ صحیح ہونے پر اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، چار پانچ مرتبہ کے تجربہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ فلاں بات سو فیصد صحیح ثابت ہوگئی، حالانکہ سو بارتجربہ نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر بکائی نے اس بات کو تسلیم کیا تو ڈاکٹر حمیداللہ نے کہا:پھر جب آپ نے صحیح بخاری کے سو میں سے اٹھانوے بیانات تجربہ کر کے درست قرار دیے ہیں تو سائنسی اصو ل کی روشنی میں آپ کو بقیہ دو بیانات بھی درست ماننے چاہییں۔ دوسری بات یہ کہ آپ انسانوں کا علاج کرتے ہیں، جانوروں کے ماہر نہیں،نہ ہی آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کتنی قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ علم حیوانات میں کون کون سے شعبے اور کون کون سی ذیلی شاخیں ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟لیکن اگر علم حیوانات میں ’مکھیات‘ کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔کیا آپ نے سروے کیا ہے کہ دنیا میں کل کتنی قسم کی مکھیاں ہیں اور کون سی مکھیاں کس موسم میں کہاں پائی جاتی ہیں؟جب تک آپ عرب میں ہر موسم میں پائی جانے والی مکھیوں کا تجربہ کر کے، ایک ایک جز کا معائنہ کرکے لیبارٹری میں چالیس پچاس سال لگا کر یہ پتہ نہ چلا لیں کہ ان میں کسی بھی مکھی کے پر میں کسی بھی قسم کی شفا نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ مکھی کے پر میں بیماری یاشفا نہیں ہوتی؟ پھر اگر آپ یہ ثابت بھی کر دیں کہ مکھی کے پر میں شفا نہیں ہوتی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ چودہ سو سال قبل ایسی مکھیاں نہیں ہوتی تھیں؟ ڈاکٹر بکائی نے اسے بھی درست تسلیم کر لیا۔ بکائی کے دوسرے اعتراض سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام آدمی کے یہ سمجھتا ہوں کہ بعض بیماریوں کا علاج تیزاب سے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں میں ایسڈ شامل ہوتے ہیں۔جانوروں کے پیشاب میں کیا ایسڈ شامل نہیں ہوتا؟ آج کے خالص اور آپ کے بقول پاک ایسڈ کے مقابلے میں ممکن ہے عرب میں اس کارواج ہوکہ کسی نیچرل طریقہ سے لیا گیا کوئی ایسا لیکویڈ جس میں تیزاب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو، بطور علاج استعمال ہوتا ہو۔ آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔ ایک انگریز سیاح ڈاؤٹی نے ۱۹۲۵ء کے لگ بھگ عرب کی سیاحت کی اوراس کے جغرافیہ پر دو بڑی زبردست کتا بیں Arabia Deserta اور Arabia Petra تحریر کیں۔ اس نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر میں بیمار پڑ گیا۔ میرا پیٹ پھول گیا، رنگ زرد ہو گیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیماری لگ گئی۔ میں نے دنیا میں جگہ جگہ اس کا علاج کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخر جرمنی میں ایک بڑے ماہر ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ جہاں تمہیں یہ بیماری لگی ہے، وہاں جاؤ۔ ممکن ہے وہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو۔ میں واپس عرب گیا۔ جس بدو کو میں نے خادم کے طور پر رکھا ہوا تھا، اس نے دیکھ کر کہا: یہ بیماری آپ کو کب سے ہے؟ میں نے کہا، کئی ماہ ہوگئے ہیں۔ اس نے کہا:ابھی میرے ساتھ چلیے۔وہ مجھے اونٹوں کے باڑے میں لے گیا اور کہا: آپ کچھ دن یہاں رہیں اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے علاوہ کچھ نہ پییں۔ میں حیرت زدہ تھا کہ ایک ہفتے کے علاج کے بعد میں بالکل ٹھک ہو گیا ۔یہ سن کر موریس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات واپس لے لیے اور اپنا مقالہ ان کے بغیر ہی شائع کر دیا۔ (محاضرات حدیث، ص ۴۵۰۔۴۵۴)
اپنے تہذیبی ورثے سے آگہی
آج کا مسلمان نوجوان اپنی فکر وتہذیب سے متعلق احسا س کہتری کا شکار نظر آتا ہے۔ڈاکٹر غازی کے بقول اس کی وجہ اپنے تہذیبی ورثے سے ناواقفیت ہے۔آپ کسی بچے سے شیکسپئر کے بارے میں پوچھیں،وہ خوب بتائے گابلکہ ممکن ہے اس کے کئی شعر بھی سنادے ،لیکن مولاناروم کا شاید اسے نام بھی معلوم نہ ہو۔لہٰذا نسلِ نو کو اپنی تہذیب وتاریخ سے آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے ۔ڈاکٹر صاحب اس سلسلہ میں اپنے ایک جاننے والے اسپینی نو مسلم مبلغِ اسلام کے اسلام کی طرف راغب ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں اسپینی حکومت نے۱۹۹۲ء میں سپین کے مسلمانوں کے زوال وانخلا کے حوالے سے پانچ سو سالہ جشن منانے کے سلسلہ میں یہ ٹاسک دیا کہ وہ ایک ایسی کتاب مرتب کریں جو ۱۴۹۲ء میں اسپین میں مسلمانوں کے زوال تک ان کی ناانصافیوں اور مظالم کی داستان پر مشتمل ہو۔ انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو عربی زبان سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے عربی سیکھی اور ذاتی مطالعہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسپین کی تاریخ کا سنہری اور زریں دور ہی وہ تھا جب یہاں مسلمان حکمران تھے۔علوم وفنون، اداروں کے قیام،عمارتوں کی تعمیر وغیرہ کا جو کام اہل اسلام کے دور میں ہوا، وہ نہ ان سے پہلے ہوا اور نہ بعد میں۔یوں اسلام سے دلچسپی پیدا ہوئی ۔پھر قرآن وحدیث کا مطالعہ کیا اور اسلام قبول کرکے اسپینی حکومت کا دیا گیا منصوبہ ادھورا چھوڑ کر تبلیغ اسلام میں لگ گئے۔ایسے ہی ایک امریکی نو مسلم فلسفہ کا مطالعہ کرتے کرتے اسلامی تصوف سے متعارف ہوئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔(محاضرات قرآنی،ص۸۲۔۸۴)
اختلافات میں انتہاپسندانہ رویہ سے اجتناب
ہمارے مذہبی حلقوں میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ علمی و فقہی اور تعبیر کے اختلاف کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے ۔ ڈاکٹرصاحب نے اپنی تحریروں اور خطبات میں اس جاہلانہ رویہ سے بچنے کی تلقین کی ہے۔انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے اختلافات نہ صرف یہ کہ نقصان دہ نہیں اور ان پر لڑنے جھگڑنے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہی یہ تھا۔ آنحضور ؐ نے صحابہ کو ایک سے زائد نقطہ ہائے نظر اپنانے کی تربیت دی ۔ اس سلسلہ میں وہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو جلد ا زجلد بنی قریظہ کے محلہ میں پہنچنے اور نمازِ عصر وہاں جا کر پڑھنے کا حکم دیا۔بعض نے یہ سمجھ کر کہ حضور ؐ کا مقصد وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھنے کو لازم قرار دینا نہیں تھا، بلکہ ممکن حد تک جلدی پہنچنا تھا،راستہ ہی میں نماز عصر پڑھ لی۔بعض دیگر نے دوسرا مطلب سمجھا اور وہاں پہنچنے پر نماز قضا ہوگئی ۔حضور نے کسی کو بھی غلط قرار نہ دیا اور دونوں سے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ایسے ہی ایک دفعہ دو صحابہؓ کو دورانِ سفر غسل کی حاجت پیش آئی اور پانی نہ ملنے کی بنا پر انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ بعد میں پانی ملا تو ایک صاحب نے غسل کرکے نماز دہرائی جبکہ دوسر ے نے کہا کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ۔حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپؐ نے پہلے شخص سے متعلق فرمایا:تمہیں دوہرا اجر ملے گا ،اور دوسرے سے کہا:تم نے سنت کے مطابق کام کیا ۔چنانچہ صحابہؓ میں باہم اختلاف ہوتا تھا۔ایک صحابی ایک عمل کو سنت سمجھتے اور دوسرے ،دوسرے کو۔گویا شریعت کے کسی حکم کو سمجھنے اور اس کی تعبیر و تشریح میں دیانت داری سے اختلاف رائے کی پوری گنجائش موجود ہے اورحکمِ شرعی کی تفسیر میں کسی شخص کی افتادِ طبع ،مزاج اور رویے کی گہری تاثیر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔شریعت کاعمومی و جامع نظام اپنے اندرمتنوع قسم کی چیزوں کو سمو لینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ القصہ اسلام میں اختلافِ آرا و مسالک ایک پسندیدہ چیز اور صحت مند سرگرمی قرار پاتی ہے۔ اسی بناپر روایات میں اہل علم کے اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ا ختلافِ افکار وآرا جیسی باعث رحمت چیز کو زحمت نہ بنائیں۔(محاضرات حدیث، ص۲۵۲،۴۷۹،۴۸۰،مسلمانوں کادینی وعصری نظام تعلیم ،ص۲۴۹۔۲۵۵۔)
شیعہ کو کافر کہنے اور کافر قرار دلوانے کی کوششوں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں : ’’دیکھیے یہ بڑی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں ۔ایسی باتیں کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔یہ دنیائے اسلام میں ایک ٹائم بم رکھنے کے مترادف ہے ۔شیعہ حضرات آج سے نہیں،تیرہ سو برس سے چلے آرہے ہیں۔ کبھی بھی مسلمانوں نے انہیں کافر نہیں کہا۔بڑے بڑے اہل علم نے شیعہ عقائد کا مطالعہ کیا تو انہیں غلط کہا،ان پر تنقید بھی کی، ان کی کمزوریاں بھی واضح کیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ بات جو پچھلے پندرہ بیس سالوں سے پیدا ہوئی ہے ،اس نے دنیائے اسلام میں بڑا فساد پید ا کیا ہے۔شیعہ کے بہت سے عقائد غلط ہیں، لیکن غلط عقائد کے علمبردار ماضی میں بھی بہت رہے ہیں۔ مثلاً خوارج کے بہت سے عقائد غلط تھے ،لیکن کسی نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت کا انکار کرنے والے پہلی صدی میں بھی تھے ،لیکن انہیں کافر نہیں کہا گیا۔کسی کی خلافت کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔قرآن میں کہیں یہ حکم نہیں دیا گیاکہ اے مسلمانو! ابو بکر و عمرؓ کو خلیفہ مانو۔جو شخص ان جلیل القدر صحابہؓ کی خلافت کا انکار کرتا ہے،وہ ایک امرِ واقعہ کا انکار کرتا ہے۔اگر کوئی انکار کرے کہ سورج نہیں نکلا ہوا تو یہ امر واقعہ کا انکار ہو گااور امر واقعہ کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوجائے گا ۔اسے بیوقوف یا جاہل کہہ سکتے ہیں۔ بیوقوف اور جاہل ہونا الگ بات ہے اور کافر ہونا الگ بات۔‘‘ (محاضرات فقہ، ص ۵۵۴)
پاکستان میں مذہبی تحزب وتشددکے محرکات اور اس سے نجات کی راہ
پاکستان میں مذہبی تحزب وتشدد ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ڈاکٹر غازی مرحوم نے ایک بالغ نظر عالم کی حیثیت سے اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس کے ظہور وشیوع کے محرکات کی نشاندہی اور اس سے بچنے کی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ان کے مطابق انگریزی استعمار نے مسلمانوں کے مسلکی اختلافات کو ان کی قوت کمزو ر کرنے کے لیے استعمال کیا۔۱۹۷۰ء میں مسلکی اختلافات انتخابی میدان میں داخل ہوئے ،انتخابی رنجشوں نے مسلکی اختلافات کی زبان اور محاورہ اپنایااور یوں بتدریج یہ چیزمسلمانوں کی تقسیم در تقسیم کا ایک خود کار ذریعہ بن گئی۔ مذہبی تشدد وتحزب کے جراثیم ۱۹۸۰ء کے عشرے میں پیدا ہوئے اور ۱۹۹۰ء کے عشرے کے آغاز میں اس مذہبی تحزب وتشدد اور دہشت گردی نے ایک عفریت کی شکل اختیار کر لی۔اس کے اسباب میں اندرون ملک کی سیاسی،معاشرتی اورمعاشی پالیسیاں اور خطے کی دیگر قوتوں کی پالیسیاں شامل ہیں۔مخصوص مذہبی عقائد کی اشاعت میں غیر ضروری سختی،بعض مذہبی سیاسی تصورات کو بزورِ بازو برآمد کرنے کی کوشش اور بعض اقلیتی خیالات وتصورات کی غیر ملکی سرپرستی،وہ چیزیں ہیں جنہوں نے صورت حال کو کشیدہ بنا دیا اورمتعدد تشدد پسند گروہ اٹھ کھڑے ہوئے۔بیرون پاکستان کی متحارب قوتوں نے اپنے آپس کے اختلافات کوپاکستان برآمد کر دیااور اپنے اپنے حامیوں کی مدد سے اپنی ذاتی جنگ پاکستان کی سر زمین پر لڑنی شروع کر دی۔اس مسئلے کا حل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دینی معاملات کو خود طے کرنا چاہیے اور غیر پاکستانی عناصر کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی ہر گز اجازت نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح غیر مسلم قوتوں کا پاکستانی سرزمین کو حربی وعسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، دوسری مسلم قوتوں کا اپنے سیاسی اور گروہی مقاصد کے لیے ہماری زمین کو استعمال کرنا بھی غلط ہونا چاہیے۔ (مسلمانوں کا دینی وعصری نظام تعلیم،ص۲۵۰۔۲۵۱،۲۵۶)
دینی تناظر میں عصری تعلیمی تقاضے
ڈاکٹر غازی مرحوم اسلامی اور جدید مغربی ہر دو علوم میں گہری بصیرت کے مالک تھے، اورجدید مسائل کو دینی تناظر میں ماہرانہ انداز سے حل کرنے کے سلسلہ میں انہوں نے قابل قدر خدمات بھی سر انجام دیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام کسی ایک یامعدودے چند اہل علم نہیں، اہل علم کی معتد بہ تعدادکا متقاضی ہے ۔ڈاکٹر صاحب نے اس تقاضے کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف بھرپور توجہ دلائی ۔وہ عصری ودینی تعلیمی نظام کو بانجھ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک تحقیق وجستجو کا ذوق نہ عصری جامعات کے فضلا میں ہے اور نہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل حضرات میں۔ اس لیے کہ تعلیم کے مقاصد واہداف ہر دو جگہ پر واضح نہیں۔یہاں ملازمت کا حصول مقصد ہے اور وہاں امامت وخطابت کا۔بلکہ مدارس کے طلبہ کو اس حوالے سے یک گونہ برتری حاصل ہے کہ اگر کسی موجودہ مسجد میں امامت وخطابت میسر نہ ہوتو اس مقصد کے لیے جہاں بس چلے،نئی مسجد کھڑی کی جاسکتی ہے اور پھر اس نئی مسجد کے وجود کا جواز پیدا کرنے کے لیے فقہی اور مسلکی حوالوں کو بہ سہولت مدد کے لیے پکاراجا سکتاہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دینی مدارس بالعموم جو فاضلین تیا کرتے ہیں، وہ دین کوموجودہ زندگی اور روز مرہ معاملات سے متعلق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔وہ جدید مسائل کو حل کرنا تو درکنار ان کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔مثلاً ان سے پوچھا جائے کہ شیئرز مارکیٹ میں پیسا لگانا جائز ہے یا نہیں تو ان میں سے اکثر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ شیئرز کہتے کس کو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں انہیں جو مسائل سکھائے جاتے ہیں، وہ اور ہی قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔چنانچہ امام صاحبان سوسائٹی میں پہنچ کرجب اپنے سیکھے ہوئے مسائل کو معاشرے سے غیر متعلق پاتے ہیں تووہ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ حضورؐ نور تھے یابشر۔ اب بیچارے عوام جن کو ان مسائل سے کوئی سروکار ہوتا ہے اور نہ ان کاعلم اور نہ ہی یہ دینی حوالے سے ان کی کسی قسم کی ضرورت ہوتے ہیں، ان مسائل میں پھنسا دیے جاتے ہیں۔ایک طرف کے حضرات اپنا زور بیان حضورؐ کو نور اور دوسرے بشر ثابت کرنے پر صرف کرنے میں جت جاتے ہیں۔لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان رہنمایانِ دین کو دینی تعلیم سے اس انداز میں بہرہ ور کیا جائے کہ وہ روز مرہ اور عام پیش آمدہ جدید مسائل میں لوگوں کی دینی رہنمائی کے اہل ہو سکیں۔ یہ تو ائمہ مساجد کی عام سطح کا معاملہ ہے۔جہاں تک ملک و ملت کو وسیع پیمانے پر جدید تناظر میں دینی حوالے سے محققانہ اور قائدانہ رہنمائی فراہم کرنے کا سوال ہے تو اس کے لیے ایسے اہل علم تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اسلامی علوم میں گہری بصیرت کے ساتھ ساتھ جدید عمرانی و انسانی علوم میں بھی ماہرانہ دستگاہ رکھتے ہوں۔حیرت ہے کہ بعض روایتی اہل علم علما کو جدید علوم سکھانے پر معترض ہوتے ہیں ۔یہ لوگ اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ یونانی فلسفہ و منطق پر مبنی مباحث آج تک مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں ،حالانکہ نہ صرف یہ کہ آج ان کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرونِ وسطیٰ میں بھی مسلمانوں میں کسی واقعی مجبوری کے بجائے محض علمی ذوق کی بنا پر رائج ہوئے،جبکہ جدید عمرانی وانسانی علوم نہ صرف یہ کہ آج انتہائی ضروری ہیں بلکہ مسلمانوں کو درپیش جدید چیلنجز کے تناظر میں واقعی مجبوری کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے الگ الگ ہونے کا کوئی تصور نہیں۔یہ مغربی سیکولرزم کے باقیات و اثرات میں سے ہے۔مسلمانوں کے دورِ عروج میں ان کا نظام تعلیم ان کی دین اور دنیا دونوں کی ضروریات پوری کرتا تھا۔آج مغربی اثرات کے نتیجے میں دینی اور دنیوی ضروریات کے لیے الگ الگ تعلیمی دھارے وجود میں آگئے ہیں ۔ہمارے مذہبی حلقے اس کو عملاً تسلیم کر بیٹھے ہیں،حالانکہ اسلام کا آئیڈیل نظام تعلیم وہ ہے جس کے ذریعے ایسے رجال کار سامنے آئیں جو مختلف شعبہ ہاے زندگی میں کارہاے نمایاں سر انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہوں۔اسلامی نظام تعلیم کو دین ودنیا کی جامعیت کا یوں آئینہ دار ہونا چاہیے کہ ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں سے کوئی مجدد الف ثانی جیسا( ہندوستان کا سب سے بڑا مذہبی عبقری کہلانے والا) عالم ہو، کوئی سعداللہ خان ایسا (مغلیہ عہد میں موجودہ ہندوستان، موجودہ افغانستان،موجودہ پاکستان ،موجودہ بنگلہ دیش،موجودہ سری لنکا اور موجودہ نیپال،کم ازکم چھ ملکوں کی وزارت عظمیٰ کو چالیس تک کامیابی سے چلانے والامدبر) سیاستدان ہو اور کوئی استاد احمد معمار جیسا( تاج محل ایسادنیا کے سات عجائبات میں سے نمایاں عجوبہ تیار کر دینے والا) انجینئر ہو۔ (مسلمانوں کا دینی وعصری نظام تعلیم،ص ۵۶،۵۷،۱۶۸،مغرب کا فکری و تہذیبی چیلنج اور علما ء کی ذمہ داریاں، ص۱۲۔۳۴)
تبلیغ و دعوت میں دین،شریعت وفقہ اورذوق کالحاظ رکھنے کی ضرورت
یہ ایک افسوس ناک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں توحیدو وحدت کے علمبردار دین کے نام پر جو تبلیغ وتلقین ہورہی ہے،وہ سوسائٹی کو متحد کرنے کی بجائے اسے مسلکوں اور فرقوں کے نام پر مختلف حصوں میں بانٹ رہی ہے ۔ سارے مبلغین اس حقیقت کو تسلیم کرتے بلکہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ تعلیم وتبلیغِ دین مسلم معاشرہ میں وحدت کی ضامن ہے، لیکن ان کی کاوشوں کا نتیجہ بالکل الٹ برآمد ہو رہا ہے ۔ یہ امرواقعہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ تبلیغ و دعوت کا کام غلط نہج پر ہورہا ہے۔ ڈاکٹر غازی علیہ الرحمۃ نے اس مرض کی تشخیص کرتے ہوئے تبلیغ ودعوت دین سے متعلق لوگوں کے لیے ایک نہایت خوبصورت نسخہ تجویز کیا ہے ۔ان کا کہنا ہے ہمارے ہاں اتحاد کی بجائے انتشار کے سامنے آنے کا سبب اسلام کی تعلیم کے حوالے سے مسلکی آرا اور فقہی اجتہادات پرزوردیاجاناہے۔ ان کے مطابق اسلام کے حوالے سے اہل مذہب کی ذمہ داریوں کی مختلف سطحیں ہیں۔ان سطحوں کا لحاظ کیے بغیر مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔یہ سطحیں دین،شریعت وفقہ اور ذوق کی ہیں۔ جہاں تک غیر مسلموں اور دین سے برگشتہ مسلمانوں میں تبلیغ کاتعلق ہے تو وہ دین ہی کی ہونا چاہیے،اس لیے کہ تبلیغ ہمیشہ دین ہی کی ہوتی ہے۔آپ نے اسلامی ادب میں کسی بھی جگہ تبلیغِ شریعت یاتبلیغِ فقہ کالفظ نہیں پڑھا ہوگا۔دین سے مراد دین کی بنیادی اساسات یعنی توحید ،رسالت اورآخرت اوران کے مقتضیات پر ایمان اور مکارمِ اخلاق ہے ۔یہ چیز ہمیشہ اور تمام اقوام وملل میں ایک سی رہی ہے۔صحابہ کرامؓ دنیا کے گوشے گوشے میں گئے، لیکن ہر جگہ دین ہی کی تبلیغ کی ۔ان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ،حضور ؐ کی نبوت ،روزآخرت کی جزا وسزا اور مکارم اخلاق کی تعلیم رہی ۔کہیں بھی کسی نے لوگوں کوکسی فقہی یاکلامی رائے یا مسلک کی طرف نہیں بلایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں فقہی اور کلامی حوالوں سے باہم کوئی اختلاف رائے موجود نہ تھا۔یہ اختلاف واضح طور پر موجود تھا لیکن اسے دعوت و تبلیغ کا موضوع نہیں بنایا گیا۔ اس لیے کہ یہ چیز تحقیق ،فتویٰ اور فہمِ شریعت کے ذیل کی ہے اور دین کے بعد کا مرحلہ ہے۔ایک صاحب علم اپنے فہم وتحقیق کے مطابق کسی فقہی وکلامی معاملہ میں ایک رائے کو زیادہ صحیح قرار دے گااور دوسرا ،دوسری کو۔یہ چیزصحابہ میں بھی موجود تھی، ائمہ سلف میں بھی موجود رہی اورآئندہ بھی موجود رہے گی ۔لیکن یہ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق سے وابستہ لوگوں کے حلقہ تک محدود رہے گی۔یہ نہ عمومی اور ابتدائی تعلیم کا موضوع ہے اور نہ تبلیغ و دعوت کا۔یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی فقیہِ اسلام نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہو کہ اے عراق والو! خبرداراحمد بن حنبل ؒ کی فلاں تحقیق غلط ہے ،اس کی بات مت ماننا۔ان حضرات نے اعلیٰ فنی اور تحقیقی موضوعات کو تحقیق کے دائرے تک محدود رکھااور دعوت ،جب بھی دی، دین ہی کی دی۔بنابریں تحقیقی معاملات میں ایک سے زیادہ آرا کی صورت میں عوام الناس محققین کی طرف رجوع کریں گے اور جس صاحب علم و تقویٰ کی تحقیق سے انہیں اتفاق ہوگا، اس کی تحقیق کو قبول کرلیں گے۔تحقیق کے بعد ایک اور چیز کسی صاحب علم کا ذوق ہے۔ اسلام نے کسی شخص کے ذوق کو ختم نہیں کیا۔صحابہ میں بھی ہر ذوق کے لوگ موجود تھے، ائمہ سلف میں بھی رہے اورآئندہ بھی موجود رہیں گے۔ بعض اوقات کسی دینی شخصیت کا ایک خاص مزاج بن جاتا ہے۔ اس شخصیت کے ماننے والے اس کے ذوق کی پیروی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں،لیکن اگر اس ذوق کو دین بنا دیا جائے اوردین کی طرح اس کی تبلیغ شروع کر دی جائے تو یہ چیز فساد کا موجب ہو گی۔ذوق تو کسی صحابی کا بھی واجب التعمیل نہیں حتیٰ کہ حضورؐ کے ذاتی ذوق کے بارے میں بھی وضاحت کر دی گئی کہ جس کا جی چاہے، اختیار کرے اور جس کا جی چاہے، اختیار نہ کرے۔مثلاً ایک مرتبہ حضور ؐ دستر خوان پر تشریف فرما تھے۔وہاں کوئی خاص قسم کا گوشت پیش کیا گیا۔آپؐ نے اس سے اجتناب کیا اور یہ عذر فرمایا کہ میرا ذوق اس کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا،لیکن صحابہ کو آپ نے منع نہیں فرمایا۔چنانچہ انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق گوشت تناول فرمایا۔
امت کی وحدت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ اور متعدد آیات میں اس کا تاکیدی حکم آیا ہے ۔حضرت ابراہیم نے دعا مانگی: ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک ۔تو جو امت قرآن مجید کی نص سے، حضرت ابراہیم کی دعا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی محنت سے قائم ہوئی ہے، جس کی وحدت اور حفاظت کی دعائیں حضورؐ نے راتوں کو جاگ کر فرمائی ہیں ،کیا اس کی وحدت کوزید ،عمر ،بکر کی رائے بنا پر افتراق و انتشار میں مبتلا کر دیا جائے؟یہ سراسر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دعوت، تعلیم، تحقیق اور ذوق کو آپس میں خلط ملط کر دیا ہے۔جو شخص تحقیق اور ذوق کی دعوت دے رہا ہے ،وہ حضورؐ اور صحابہؓ کے عمل کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ امر کس قدر افسوسناک ہے کہ لوگ قرآن کی بجائے تراجم قرآن اور رسول ؐ واصحاب رسولؓ کے طرز عمل کی بجائے اپنے اپنے ممدوح علما کے مسالک و مشارب کی دعوت دیتے ہیں ۔اس پر مستزاد یہ کہ اپنے اپنے ممدوح علما سے اختلاف کو کفر و نفاق تک پہنچانے میں ذرا تامل نہیں کرتے۔ لوگوں نے قرآن کو مختلف ترجموں اور تفاسیر کی تنگنائیوں میں محدود کر ڈالا ہے،حالانکہ کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو،حتیٰ کہ عمر فاروقؓ ایسا جلیل القدر صحابی ہی کیوں نہ ہو ،اس سے قرآن کی تعبیر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے محسوس کیا کہ لوگ مہر مقرر کرنے میں بہت اسراف سے کام لینے لگے ہیں اور اسے بڑائی کی دلیل سمجھا جانے لگاہے،لہٰذا اس پر قدغن لگانی چاہیے۔انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد مہر کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی گئی ہے اور کوئی شخص اس سے زیادہ مہر نہ رکھے ۔بڑے بڑے جید صحابہؓ موجود تھے،سب نے اس فیصلہ کو درست قرار دیا۔نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمرؓ باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتون ملیں اور حضرت عمرؓ سے کہا: تم نے جو مہر مقرر کیا ہے ،وہ بالکل غلط ہے ۔تم قرآن کو نہیں سمجھتے ۔قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ اگرتم نے عورت کودولت کا ایک ڈھیر بھی دے دیا ہو توبھی واپس مت لو۔گویا دولت کا ڈھیر بھی مہر ہو سکتا ہے۔لہٰذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس مقررہ مقدار سے زیادہ مہر نہ باندھا جائے ؟حضرت عمرؓ نے ایک لمحے کو سوچا۔مسجد میں آئے، لوگوں کو بلایا اور منبر پر چڑ ھ کر فرمایا: اخطا عمر واصابت امرأۃ۔ ’’عمر نے غلطی کی اور ایک عورت نے سچ کہا۔‘‘ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ یہ عمرؓ وہ تھے جو خلیفہ راشد تھے۔حضورؐ کے جانشین تھے۔قرآن مجید کی ۱۷ آیات جن کی توقع اور اندازہ کے مطابق نازل ہوئیں۔حضورؐ نے بارہا جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی تائید فرمائی۔اس کے بر عکس آج کا کوئی مذہبی لیڈر، مولوی یا پیر ہوتا تو بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والی عورت کو ڈانٹ کر خاموش کر دیتا۔اگر عمرؓ ایسے مقام و مرتبہ کے حامل شخص سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ علی الاعلان اس کا اعتراف کر سکتے ہیں تو اور کون کس شمار وقطار میں ہے؟مگر ہمارے ہاں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ عمر فاروقؓ سے غلطی ہو گئی ،امام شافعیؒ اور امام مالکؒ سے غلطی ہو گئی، ہماری دینی درسگاہوں میں روزانہ یہ تنقیدی تبصرے ہوتے رہتے ہیں ،لیکن یہ کہنے کی کسی کی مجال نہیں کہ مولانا تھانوی سے غلطی ہو گئی ،مولانا مودودی سے غلطی ہو گئی یا مولانا احمد رضا خان سے غلطی ہو گئی۔کوئی ذرا یہ جرات کرکے تو دیکھے!ان کے مریدین سر توڑ دیں گے اور اسلام سے خارج کر کے دم لیں گے۔ (محاضرات قرآنی، ص ۳۸۰۔۴۰۱، محاضرات سیرت، ص ۷۵۳)
مقصودِ اصلی حکومت کا قیام نہیں، معاشرہ کی اصلاح ہے
ہمارے ہاں بہت سے اہل مذہب اپنی تمام تر توانائیاں حکومت کے حصول میں صرف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اوراسلامی خطوط پر اصلاحِ معاشرہ کی بنیادی ذمہ داری سے غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں۔یہ رویہ معاشرے اور ریاست ہر دو کی اسلامی تشکیل میں سدِ راہ ہے۔ ڈاکٹر غازی ؒ نے اہل مذہب کو مذہبی خطوط پر معاشرہ کی تعمیر کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا اور اس با ت پر زور دیا ہے کہ اسلام میں اصلاح کی ترتیب اوپر سے نیچے کی بجائے نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔حکومت مسلمانوں کا مقصود اصلی نہیں۔قرآن مجید میں کہیں بھی مسلمانوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانو!تم حکومت قائم کرو ،بلکہ امت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم میں ایک ایسی امت ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے ۔ہاں اس کام میں اگر حکومت رکاوٹ بنتی ہے تو اس کی اصلاح کرواور اگر اللہ تم میں سے کسی کو حکومت عطا فرما دے تووہ اسے اسلام کے مطابق چلائے ۔شریعت کی اصطلاح میں ایک ’’ مطلوب لعینہ‘‘ ہوتا ہے اور ایک’’ مطلوب لغیرہ‘‘، یعنی ایک چیز بذات خود مقصد ہوتی اور دوسری حصول مقصد کا ذریعہ۔اسلام کے نقطہ نظر سے حکومت مقصود لعینہ نہیں، مقصود لغیرہ ہے۔ریاست شریعت کی ضرورت ہے ،لیکن ریاست اور شریعت لازم و ملزوم نہیں۔ کیا امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں،وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے؟کیا فتح مکہ سے پہلے مکہ میں رہنے والے مسلمان شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے؟کیا حبشہ میں ہجرت کر کے جانے والے مسلمان شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے؟شریعت پر عمل ریاست کے بغیر بھی ممکن ہے ۔ہاں البتہ شریعت کی ریاستی ذمہ داریاں ریاست کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں اور اسی اعتبار سے مکمل اسلامی احکام کے مطابق اسلامی ریاست کا قیام ہم سب کی آرزو ہے، لیکن اس آرزو کی تکمیل کے لیے پھر سوسائٹی ہی کی اصلاح کو فوکس کرنا لابدی ٹھہرتا ہے۔ ریاست اسی وقت اسلامی بن سکے گی جب معاشرہ اسلامی ہو گا۔یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ کے افراد کی اکثریت اسلام سے بے بہرہ ہو،عبادات کی پابند نہ ہو، چوری، بدکاری جھوٹ اور دیگر جرائم میں مبتلا ہو اور حکومت حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ جیسی قائم ہو جائے۔ کسی نے حضرت علیؓ سے پوچھا:کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں بہت امن تھا، مگر آپ کے دور میں بدامنی ہے؟انہوں نے فرمایا :اس لیے کے وہ میرے جیسے لوگوں پر حاکم تھے اورمیں تم جیسے لوگوں پر حاکم ہوں۔ (محاضرات سیرت، ص۳۷۲،۳۷۴،۳۸۲ وغیرہ)
غیر مطلوب اور بے فائدہ مذہبی مباحث سے احتراز
اسلام مسلمانوں میں جو رویے پیدا کرنا چاہتا ہے ،ان میں ایک نہایت اہم رویہ مذہب کے حوالے سے ایسے مباحث سے احتراز ہے جن کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو،لیکن ہمارے ہاں بد قسمتی سے نہ صرف یہ کہ ایسے بے فائدہ اور غیر مطلوب مباحث سے احتراز نہیں کیا جاتا بلکہ الٹا انہی کو مرکزِ بحث و نظر اور شناختِ ایمان بنا لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر غازی مرحوم نے اس افسوسناک رویہ کو ترک کرنے پر زور دیا ہے ۔ٍ حضور ؐ کے علم سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک غیر ضروری اور بے فائدہ سوال ہے ۔ہمیں ایسے سوالات پر اپنا وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔قیامت کے روز ہم سے حضور ؐ کے احکامات اور آپ کی سیرت کے مطابق عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، حضور کے علم کی کوانٹٹی سے متعلق ہر گز سوال نہیں ہو گا ۔مذکورہ سوال کی لغویت کو منطقی اعتبار سے واضح کرتے ہو ئے فرماتے ہیں کہ حضورؐ کے علم کا تقابل عام انسانوں سے کوئی فضول شخص ہی کر سکتا ہے،کیونکہ عام انسانوں کے مقابلہ میں حضور کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ اور حضو ر کے علم کا تقابل اس اعتبار سے بے فائدہ مشغلہ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں حضور کے علم کا محدود ہونا ظاہر وباہر ہے۔کسی شخص کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ حضور کے پاس اتنا علم تھا۔ہم میں سے کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ حضور کے پاس غیب کا اتنا علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔گویاایسے سوالات بحث و نظر کا موضوع ہی نہیں ہونا چاہییں۔جب کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ انسانی بساط ہی میں نہ ہو تو اس پر بحث چہ معنی دارد؟(محاضرات سیرت، ص ۵۱۱، ۵۷۶ وغیرہ)
خذ ماصفا ودع ماکدر کا رویہ
ہمارے مذہبی حلقوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت اورفکری وابستگی ہے ،اس کی تو ہر کمزور سے کمزور چیز بھی صحیح اور لائقِ تقلید ہے اور جس سے یہ وابستگی و عقیدت نہیں، اس کا اچھے سے اچھا کام بھی ناقابلِ التفات۔یہی نہیں بلکہ اپنے فکری رہبر کی غلط سے غلط بات کے دفاع میں اور دوسرے کی صحیح سے صحیح بات کی تردید میں ’خود بدلتے نہیں قرآں کوبدل دیتے ہیں‘ کامصداق بن جاتے ہیں ۔ڈاکٹر صاحب نے اس رویے پر تنقید کرتے ہوئے خذ ما صفا ودع ما کدر کا رویہ اپنانے پر زور دیا ہے ۔ایک خطبہ میں ڈاکٹر صاحب نے سیرت سے متعلق سر سیدکی خدمات کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے سر سید کی تجدد پسندانہ تعبیرات کی بنا پر مذہبی حلقوں میں ان سے متعلق پائی جانے والی ناپسندیدگی کے تناظر میں ان سے بہت سے سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ ہمارے ہاںیہ روایت بن گئی ہے کہ یا تو ہر چیز کو بالکل منفی انداز میں دیکھا جاتا ہے یا بالکل عقیدت مندانہ انداز میں۔ضروری نہیں کہ کسی شخص کی ایک بات سے آپ متفق ہوں تو اس کی بقیہ تمام باتوں سے بھی آپ اتفاق کریںیا اگر ایک سے اختلاف ہے تو بقیہ سب باتوں سے بھی اختلاف کریں۔یہ رویہ ایک مسلمان کے شایانِ شان نہیں۔سر سید کی بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے ۔ان کی بہت سی باتیں مغرب سے مرعوبیت کا نتیجہ تھیں۔لیکن ان کی مثبت باتوں اور مسلمانوں کے لیے خدمات کو سراہنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کسی سے اتفاق کی صورت میں اس کے ہررطب ویا بس کو درست مان لینے اور اختلاف کی صورت میں ہر بات کا انکار کر دینے کا کوئی جواز نہیں۔ (محاضرات سیرت،ص۶۳۲،۶۳۹،۶۴۰)
ایک نئی اور عالمگیرفقہ کی تشکیل کی ضرورت اور اجتہاد وتقلید کی حقیقت
نئے زمانے کی ضروریات کے مطابق ایک نئی فقہ کی تشکیل کے بغیر اسلام کے عالمگیر کردار کا خواب شرمندۂ معنی نہیں ہوسکتا۔حکیم الامت علامہ محمد اقبالؒ نے بھی اس پر بہت زور دیا تھا۔ڈاکٹر غازی ؒ نے بھی اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ان کے مطابق آج کا دور بین الاقوامیت کا دور ہے۔اسلامی عالمگیریت کے لیے نا گزیر ہے کہ ایک نئی اور عالمگیر فقہ تشکیل دی جائے۔اس فقہ کو Cosmopliton Fiqh یا Globalized Fiqh کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس فقہ کی تدوین کے لیے ہمیں قدیم اسلامی روایت کے ساتھ گہری اور مضبوط وابستگی کے ساتھ ساتھ مشرق و مغرب کے تمام مفید تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔انہوں نے جدید دور میں عالمگیریت کے مسائل کی بنیادی اہمیت کوواضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر دور میں بعض اہم فکری مسائل اور تہذیبی معاملات ایسے ہوتے ہیں ،جو کسی وجہ سے خصوصی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں ۔مثال کے طور پر بیسویں صدی کے نصف اول میں اسلامی اور غیر اسلامی، ہر فکر، ریاست وسیاست پر مرتکز تھی ۔اس زمانہ کے تمام مفکرین اسلام اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست پر لکھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے نصف دوم میں ریاست اور سیاست کی مرکزیت کم ہوگئی اور اقتصادیات و مالیات کی مرکزیت نمایاں ہو گئی ۔چنانچہ فکر اسلامی کا اہم موضوع سیاست اور ریاست کی بجائے اقتصادیات و مالیات کے مضامین قرار پائے۔آئندہ پچاس سال میں، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ عالمگیریت اور اس کے مسائل اور گلوبلائزیشن اور اس کے مسائل،فکر کے بنیادی مسائل ہوں گے۔لہٰذا ہماری ذمہ داری، آئندہ چندعشروں میں، یہ ہے کہ ہم عالمگیریت کی فکری واخلاقی اساس کا تعین کرنے میں دنیا کی رہنمائی کریں اور دنیا کو مذہب اور معاشرے، مذہب اور تہذیب، مذہب اور ریاست اورمذہب اور معیشت کا بھولا ہواسبق دوبارہ یاد دلائیں۔یہ کام چونکہ اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اجتہاد پر بھی خصوصیت سے زور دیا اور اس کا ختم نبوت سے قریبی تعلق بتایا ہے۔ لیکن اجتہاد کے حوالے بعض لوگ اس غلط فہمی کاشکار ہوجاتے ہیں کہ یہ ائمہ فقہ کے اجتہادات سے بغاوت کی راہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس غلط فہمی کے ازالہ کی خاطر اجتہاد کی اہمیت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اجتہاد اور تقلید کی حقیقت بھی واضح فرمائی ہے۔لکھتے ہیں کہ بعض اعتبارات سے تقلید کے بغیر کوئی چارۂ کار نہیں ہوتا۔اگر کوئی شخص دین کا تفصیلی علم حاصل نہ کر سکے یا نہ کرے(کہ شریعت نے اسے سب پر لازم قرار نہیں دیا)تواس کے لیے شریعت کے مختلف فیہ امور میں اس کے سوا کوئی سبیل نہیں کہ جس کے علم وتقویٰ پر اسے اعتماد ہو، اس کے اجتہادات کے مطابق عمل کرے۔ ایسی تقلید ہمیشہ رہی اور ہمیشہ رہے گی۔یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سائنس سے ناواقف شخص کسی سائنسی معاملے میں کسی ایسے سائنسدان کی رائے کو تسلیم کرے جس کے سائنسی علم پر اسے بھروسہ ہویا کوئی معاشی معاملات سے بے خبرشخص کسی ایسے ماہر معاشیات کی رائے پر اعتمادکرے جس کے معاشی علم اور مہارت پر اسے اعتماد ہو، لیکن اس تقلیدکا تعلق روزمرہ زندگی اور معاشرے کی اسلامی اساس اور اس کے تسلسل سے ہے۔ مستقبل کی تشکیل اور نقشہ کشی، نئے چیلنجز کا سامنا کرنے، نئے مسائل کو حل کرنے، نئی مشکلات کا دور کرنے اور نئے سوالات کے جوابات کے لیے جرأت مندانہ اجتہاد ناگزیر ہے۔ لہٰذا اہل علم وبصیرت کو آگے بڑھ کر اسلام کے عالمگیر کردار کے لیے وہ تمام تد ابیر اختیار کرنا چاہییں،جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ان تدابیر کے لیے نئے نئے ادارے بھی بنائے جائیں اورماضی کے اداروں کا احیا بھی کیا جائے ۔شریعت نے نہ ماضی کے کسی ادارے اور تجربے کو جوں کا توں اختیار کرنے کا حکم دیاہے اور نہ غیر ضروری طور پر کسی نئے ادارے یا تجربے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔اس لیے کہ شریعت کا اصل زور مقاصد واہداف اور نصوص کی تعمیل پر ہے نہ کہ وسائل و ذرائع پر۔(محاضرات شریعت،ص۵۴۰۔۵۵۲)
ڈاکٹر غازی مرحوم کے افکار ونظریات کے بہت سے گوشوں میں سے صرف چند گوشے یہاں پیش کیے جا سکے ہیں، لیکن ان سے بھی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرحوم کس قدر اتھاہ وژن،عمیق فکر ،گہری بصیرت اور وسیع علم کے حامل تھے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے افکار سے رہنمائی حاصل کرکے ان کے امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے خواب کو شرمندۂ معنی کرنے کی سعی کی توفیق عطافرمائے۔ قضا وقدر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کوکچھ مزید مہلت ملتی تووہ اس امت مرحومہ کے لیے وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جس کاخواب دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ فکر کی تنگنائیوں کو پہنائیوں میں بدلنے، بے مایہ کو گراں مایہ کرنے، قطرے کو گہر کرنے اور اپنے افکارِ تازہ سے جہانِ تازہ تخلیق کرنے کی اہلیت کے مالک تھے۔ شاید اسی احساس کے تحت انہوں نے عرفی کی زبان میں کہا تھا:
من از گل باغ می جویم تو گل از باغ می جوی
من آتش از دخاں بینم تو از آتش دخاں بینی
’’میں پھول سے باغ بنانا چاہتا ہوں اور تم باغ سے پھول تلاش کرتے ہو۔ میں دھویں سے آگ کا پتہ چلا لیتا ہوں اور تم آگ کو دیکھ کر دھویں کا وجود معلوم کرتے ہو۔‘‘
کاسموپولیٹن فقہ اور ڈاکٹر غازیؒ کے افکار
محمد سلیمان اسدی
برصغیر پاک وہند کی سرزمین پر گزشتہ دو اڑھائی صدیوں میں بعض ایسی نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے علمی بنیادوں پر لوگوں میں فکری جمود کو توڑتے ہوئے اجتہادی عمل کو آگے بڑھانے اور مسلکی انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ ان اہل علم میں شاہ ولی اللہؒ ، علامہ اقبالؒ ، مولانا انور شاہ کشمیریؒ ، مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کے نام سرفہرست ہیں۔ بیسویں صدی کے اوائل میں علامہ اقبالؒ نے زمانہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور تمدنی و تہذیبی تغیرات پر گہری نظر رکھتے ہوئے فقہ اسلامی پر نئے زاویوں سے غور وفکر کرنے اور اسے از سر نو مرتب کرنے کے لیے دعوت فکر دی اور اس سلسلے میں مختلف نامور اہل علم سے رابطہ بھی کیا تھا۔ ان میں علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ ، مولانا سید سلیمان ندوی ؒ اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ؒ کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۲۶ ء میں مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند سے الگ ہوئے تو علامہ اقبالؒ کو اس سے خوشی ہوئی کہ شایداب وہ مولانا انور شاہ کشمیری ؒ کو قیامِ لاہور پر راضی کر سکیں گے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی لکھتے ہیں:
’’دارالعلوم دیوبند میں اختلافات کے باعث جب حضرت الاستاذ [مولانا انور شاہ کشمیری] نے ا پنے عہدہ صدر الاساتذہ سے استعفا دیا اور یہ خبر اخبارات میں چھپی تو اس کے چند رو ز بعد میں ایک دن ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمانے لگے کہ آپ کا اور دوسرے مسلمانوں کا جوبھی تاثر ہو، میں بہرحال شاہ صاحب کے استعفا کی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے بڑے تعجب سے عرض کیا : کیا آپ کو دارالعلوم دیوبند کے نقصان کا کچھ ملال نہیں؟فرمایا کیوں نہیں، مگر دارالعلوم دیوبند کو تو صدرالمدرسین اور بھی مل جائیں گے اور یہ جگہ خالی نہ رہے گی، لیکن اسلام کے لیے جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چاہتا ہوں، اس کو سوائے شاہ صاحب کے کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس اجمال کی تفصیل یہ بیان کی کہ آج اسلام کی سب سے بڑی ضرورت فقہ کی جدید تدوین ہے جس میں زندگی کے ان سینکڑوں ہزاروں مسائل کا صحیح اسلامی حل پیش کیا گیا ہو جن کو دنیا کے موجودہ قومی اور بین الاقوامی، سیاسی، معاشی اور سماجی احوال وظروف نے پیدا کر دیا ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ اس کام کو میں اور شاہ صاحب دونوں مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی شخص اس وقت عالم اسلام میں ایسا نظر نہیں آتا جو اس عظیم الشان ذمہ داری کا حامل ہو سکے۔ پھر فرمایا: یہ مسائل کیا ہیں اور ان کا سرچشمہ کہاں ہے؟ میں ایک عرصہ سے ان کا بڑے غور سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ یہ سب مسائل میں شاہ صاحب کے سامنے پیش کروں گا اور ان کا صحیح اسلامی حل کیا ہے؟ یہ شاہ صاحب بتائیں گے ۔ اسی طرح ہم دونوں کے اشتراک وتعاون سے فقہ جدید کی تدوین عمل میں آئے گی‘‘ (۱)
چنانچہ علامہ اقبال ؒ نے مولانا انور شاہ کشمیری ؒ کو ایک تفصیلی تار بھیجا جس میں کہا گیا کہ آپ لاہور تشریف لے آئیں اور یہاں قیام فرمائیں۔ اس تار کا جواب نہ آنے پر انھوں نے مولانا عبدالحنان ہزاروی کو براہ راست بات کرنے کے لیے روانہ کیا کہ تم جا کر زبا نی عرض کر و۔ مولانا عبدالحنان ہزاروی کہتے ہیں کہ میں گیا تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کو وہ تار اس وقت دیا گیا جب ڈابھیل والوں نے اصرار کر کے شاہ صاحب کو وہاں تشریف لے جانے پر رضا مند کر لیا تھا ۔ میں ملا تو فرمایا، افسوس کہ آپ کا پیغام بعد میں ملا اور میں ڈابھیل والوں سے وعدہ کر چکا تھا۔ (۲)
۲۹؍مئی ۱۹۳۳ء کو شاہ صاحب کا وصال ہو جانے کے بعد علامہ اقبال نے مولانا سید سلیمان ندویؒ کو اس بات پر غور وفکر پر آمادہ کرنے کے لیے متعدد خطوط لکھے کہ وہ دیگر اہل علم کے ساتھ مسلمانانِ عالم کو پیش آنے والے ممکنہ چیلنجز کا حل تلاش کرنے کے لیے فقہ اسلامی کا ازسرنو جائزہ لے سکیں۔ (۳) مگر یہ دونوں اہل علم بوجوہ علامہ محمد اقبال ؒ کے ساتھ مل کر کام نہ کر سکے۔ اسی طرح علامہ اقبال ؒ نے اپنی عمرکے آخری سال ۱۹۳۸ء میں مشرقی پنجاب کے ضلع پٹھان کوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صاحب ثروت مخلص بزرگ نے اس ادارہ کے لیے زمین بھی دے دی ۔ اس میں یہ طے کیاگیا کہ ایک نوجوان عالم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو بلایا جائے ۔ خود موصوف بھی وہاں جایا کریں گے۔ اس طرح وہ مل کر فقہ اسلامی کی تدوین نو کا کام کریں گے اور جدید دور کی ضروریات کے مطابق فقہ اسلامی کے قواعد و ضوابط کو از سر نو مرتب کیا جائے گا۔ (۴)
اسی تناظر میں بیسویں صدی کے آخر میں بہت سے اہل علم ودانش کے ہاں یہ احساس شدت سے پیدا ہونے لگا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج (Global village) کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، بہت سے پیچیدہ معاملات کی گتھیاں سلجھنے لگی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر تعلقات اور رابطوں کے راستے ہموار ہو نے لگے ہیں۔ پھر یہ کہ عالم اسلام کے بیشتر ممالک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا عمل سنجیدگی سے آگے بڑھنا شروع ہوا ۔ اب جہاں جہاں اسلامی قوانین کی بات ہوئی، وہاں اسلامی قوانین پر اعتراضات بھی ہوئے۔ یہ اعتراضات مغرب نے بھی کیے اور دنیاے اسلام کے اندر سے بھی ہوئے۔ مثلاً عورتوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں ، روز مرہ پیش آمدہ معاملات و حادثات کے بارے میں اشکالات کا دنیائے اسلام کو واسطہ پڑنے لگا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلاکہ عالم اسلام کے مختلف اہل علم و دانشور حضرات نے سنجیدگی سے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تمام فقہی مسالک سے استفادہ کرنے کا سوچا۔ اجتماعی اجتہاد کے اس رجحان کے نتیجے میں فقہی مسالک کی روایتی حدود، محدود اور کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ عالمی حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اب ایک نئی فقہ وجود میں آ رہی ہے جس کو نہ فقہ حنفی کہہ سکتے ہیں، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ جعفری، بلکہ اسے اسلامی فقہ ہی کہا جانے لگا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ نے اپنے خطبات اور محاضرات میں اس کے لیے Cosmopolitan Fiqh یعنی عالمی یا ہردیسی فقہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ (۵)
ڈاکٹر غازی صاحب ؒ نے اس کی ضرورت اور عملی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اہل علم کو اس کی طرف توجہ دلانے اور سنجیدگی سے سوچنے کی دعوت عمل دی ہے کہ عصر حاضر میں اس کی ضرورت اس وقت واضح ہو کر سامنے آئی جب بنکاری کے نظام کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوششیں کی گئی تو عالم اسلام میں اور خصوصاً سر زمین پاکستان میں اس کی تیار ی کے لیے مختلف فقہی مسالک و مکاتب فکر کے اہل علم اور ماہرین معاشیات سے رپورٹ لی گئی تو اس کے نتیجے میں اسلامی بنکاری کا جو خاکہ مشترکہ جدوجہد اور لائحہ عمل سے تیار ہوا، وہ کسی مخصوص فقہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کو فقہ حنفی کی دستاویز یا رپورٹ نہیں کہا جا سکتا اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فقہ شافعی یا فقہ جعفری کی بنیاد پر تیار ہوئی ہے۔ اس میں پوری فقہ اسلامی سے استفادہ کیا گیا اور دستاویز تیار کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اسے ایک بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے کہ دنیائے اسلام کے مشکلات کے حل کے لیے مشترکہ فقہی پلیٹ فارم سے استفادہ کیا گیا ہے اور عملی طور پر اس پر عمل درآمد کرایا گیا ہے۔
ڈاکٹر صاحب ؒ اسے اس زاویہ نگاہ سے اس لیے دیکھتے تھے کہ تمدنی تغیرات اور زمانے کے تقاضوں میں اس قدر تغیر رونما ہو چکا ہے کہ اگر ایک فقہ کے ماننے والوں نے دوسری فقہ سے استفادہ نہ کیا تو ان کے لیے موجود چیلنجز سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی وضاحت ایک مثال سے کرتے ہیں کہ
’’اگر کوئی شخص آپ سے کوئی وعدہ کر لے کہ مثلاً وہ آپ سے آپ کی فیکٹری کی مصنوعات خرید لے گا تو کیا اس وعدہ کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے یا صرف اخلاقی حیثیت ہے؟ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ اس طرح کا وعدہ قضاءً ا واجب التعمیل نہیں ہے۔ اس کے برعکس امام مالکؒ نے فرمایا کہ اگر کسی وعدہ کے نتیجہ میں کوئی شخص کسی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لے اور اس ذمہ داری کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو ایسے ہر وعدہ کی پابندی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ عدالتوں کو ایسے معاملات میں مداخلت کا پورا اختیار ہے اور ملکی قانون ایسے وعدوں کی لازمی تعمیل کرانے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اب یہ دو نقطہ نظر ہیں۔ دونوں اجتہادی ہیں،کوئی نص صریح یا حدیث میں نہیں ہے۔ آج کل کا جو کاروبار ہے، وہ پرانے زمانے کے کاروبار کی طرح نہیں ہے کہ دو آدمیوں نے مل کر دکان کھول لی یا ایک آدمی، دو چار یا دس آدمیوں کا مال لے کر قافلہ میں چلا گیا اور جا کر تجارت کر کے آ گیا۔ دیانت دار نے تو بتا دیا کہ کس کو کتنا منافع ملا ہے جس کا یہ حساب ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنا آدمی بھی ساتھ دیا کرتے تھے کہ دیکھتا رہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل کیفیت یہ ہے کہ کوئی کاروبار ایسا نہیں جس میں لاکھوں کروڑوں آدمی بیک وقت شریک نہ ہوں۔ بڑے بڑے کاروباروں کے شیئرز دس روپے میں مل جاتے ہیں۔ اس شیئر کو جس کاجی چاہے خرید لے۔ اگر بنکوں کو مضاربہ کمپنیوں کے طور پر چلانا ہے تو جتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، وہ ا س میں شریک ہوں گے اور سب رب المال ہوں گے، پاکستان میں غالباً ساڑھے تین کروڑ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں۔ تین ساڑھے تین کروڑ اکاؤنٹ ہولڈروں کے کاروبار میں یہ کہاں ممکن ہے کہ آدمی یہ دیکھنے کے لیے رکھا جائے کہ کاروبار صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس لیے اس پر از سر نو غور کرنا پڑے گا۔ اتنے بڑے پیمانے پر جو کاروبار ہوتا ہے، اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ فرض کریںآپ کوئی کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں آج کل جو قانون ہرجگہ رائج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کمپنی کا تصور اپنے ذہن میں واضح کریں جو آپ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کمپنی کا ایک بنیادی ڈھانچہ تیار کریں جو میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کہلاتا ہے۔ اس میں آپ واضح طور پر یہ بتائیں گے کہ وہ کمپنی کیا کرے گی۔ اس میں آپ کتنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں۔ کتنے پیسے آپ ابھی دینے کے لیے تیار ہیں اور کتنے بعد میں دیں گے۔ آپ شیئرز کے نام پر پبلک سے کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ ایک کو آتھورائزڈ کیپٹل یا اجازت شدہ سرمایہ کہتے ہیں اور دوسرے کو پیڈ اپ کیپٹل یا ادا شدہ سرمایہ کہتے ہیں ۔ پیڈاپ کیپٹل کتنا ہو گا اورا آھورائزڈ کیپٹل کتنا ہو گا ۔ جو اصل سرمایہ آپ لگا رہے ہیں وہ کتنا ہو گا ، کسی اور شخص نے اگر ذمہ لیا ہے جس کو انڈر رائٹنگ کہتے ہیں، وہ کون شخص ہے اور اس نے کتنا ذمہ لیا ہے۔ اگر اس نے کچھ شرائط رکھی ہیں تو وہ کیا ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ کو وہ کمپنی حکومت کے پاس رجسٹر کروانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کمپنی کے articles of association بنانے پڑتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی کے تفصیلی قواعد اور ضوابط کیا ہیں۔ پھر حکومت کے قواعد وضوابط کے مطابق آپ اس بارے میں اخبار میں اشتہار دیں گے۔ اس اشتہار کے ذریعے آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون کون لوگ اس میں شریک ہیں۔ ان کی credibilityکیا ہے۔ وہ کتنے نفع کی توقع کرتے ہیں۔ اس کے حساب سے لوگ اس میں پیسہ لگائیں گے اور سرمایہ کار ادارے اس میں پیسہ دیں گے۔ اب یہ اربوں کھربوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ خود اس اعلان کے مرحلہ تک پہنچنے کے لیے کئی کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کئی کروڑ یا کئی لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کئی کروڑ یا کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ آ پ کمپنی لانچ کرنے کی بات کریں۔
خالص احناف کے ٹھیٹھ نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ سب کچھ محض ایک وعدہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ آپ پیسہ دیں تو اس میں نفع ہو گا ۔اب یہ وعدہ ، جو انہوں نے کیا ہے ،کیا یہ بائنڈنگ نہیں ہے؟ اگر یہاں احناف کا نقطہ نظر اپنایا جائے تو اس طرح کا کوئی کاروبار تو چل ہی نہیں سکتا۔ محض ایسے وعدے جو عدالت میں واجب التعمیل نہیں ہے اور جس کو عدالت نافذ نہیں کرے گی، اس میں کوئی آدمی اپنا پیسہ کیوں لگائے گا۔ اس پر غوروخوض شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ امام مالکؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں کوئی obligationیا liability پیدا ہوتی ہے تو وہ وعدہ قضاءً ا واجب التعمیل ہے اور عدالت اس کی لازمی پابندی کا حکم دے گی۔ چنانچہ آج کل کے تمام فقہا نے اس رائے کو اختیار کر لیا۔ اب جہاں جہاں اسلامی فنانسنگ، بینکنگ یا کمپنی پر کام ہو رہا ہے، وہا ں امام مالکؒ کے اسی نقطہ نظر کے مطابق ہو رہا ہے۔‘‘ (۶)
ڈاکٹر صاحبؒ کے نقطہ نظر کا کئی اعتبار سے قوی ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ تمدنی تغیرات کے نتیجے میں اتنے پیچیدہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ کسی ایک فقہ میں رہتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان مسائل کا حل تلاش کرنا مشکل ہے، بلکہ بعض جگہ ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ چار مشہور فقہی مسلکوں کے دائرے سے نکل کر بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام کی کثیر جماعت نے اس طرف رجوع کیا ہے کہ براہ راست قرآن و سنت سے استنباط کر کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ اس صورت میں کسی بھی امام کے قول پر عمل کرنا ہو ، قبول کر لینا چاہیے۔ تاہم یہ اجتہاد واستنباط کی صلاحیت رکھنے والے اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ اس دوران اگر ائمہ اربعہ کے اقوال سے انحراف ہو جاتا ہے تو کوئی بری با ت نہیں ہو گی۔
جہاں تک پیش آمدہ مسائل کے اجتہاد واستنباط کی بات ہے تو ڈاکٹر غازی ؒ فرماتے ہیں کہ اجتہاد و استنباط کی پیچیدگیوں سے الجھنا اور سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس اس کا بیڑا اٹھا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہر کس و ناکس کا کام نہیں کہ اٹھ کر کہہ دے کہ میں چاروں فقہا کے نقطہ نظر کو مسترد کرتا ہوں۔ ایسا نقطہ نظر جس پر چار جید ترین فقہا کے زمانہ سے لے کر ہزاروں بلکہ لاکھوں فقہا نے غور وفکر کیا، جو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے لوگ تھے، پھر ہزاروں لاکھوں انسان مسلسل اس پر غور کرتے چلے آرہے ہیں، ایک ایک پہلو ر صدیوں تک غور کیا گیا، اس سارے کام کو کوئی آدمی آج کھڑا ہو کر بیک جنبش زبان یہ کہہ دے کہ میں مسترد کرتا ہوں، یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اس میں بہت تفصیلی غور وخوض کے ساتھ بڑی خداترسی، احساس ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ (۷)
ڈاکٹر صاحبؒ کے فکر کی تائید کے لیے ہم ذیل کی سطور میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں جن میں فقہ حنفی سے وابستہ لوگوں کے لیے اپنی فقہ پر عمل کرنا دشوار نظر آتا ہے او ر اسی لیے وہ زمانہ کے تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے دیگر فقہائے کرام ؒ کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں:
مثال کے طورپر دلالی brokerage)) کی اجرت کولیجیے۔ اگر دلال اپنی اجرت اور کمیشن بائع اور مشتری سے واضح طور پر طے کر لے تو فقہ حنفی سے وابستہ لوگوں میںیہ صورت معاملہ عام پائی جاتی ہے اور اسے جائز سمجھا جاتا ہے، جب کہ اگر فقہاے احناف ؒ کی رائے لی جائے تو یہ ان کے ہاں ناجائز ہے اور اس سے آپس میں طے پانے والا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ (۸) تاہم فقہائے مالکیہ کے ہاں مذکورہ صورت جائز ہے اور اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔(۹) احناف ؒ کے نزدیک فیصد کے حساب سے دلال کی اجرت مقرر کرنا ناجائز ہے،جب کہ امام مالک اور امام احمد ؒ کے ہاں جائز ہے۔ تاہم متاخرین حنفیہ میں سے علامہ ابن عابدین ؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ نے امام ابوحنیفہؒ کے قول کو ترک کرتے ہوئے امام مالک اور احمدؒ کے قول کو قبول کرنے کا کہا ہے ۔ (۱۰)
اسی طرح بین الاقوامی سطح کی تجارت پر شپنگ کا جو طریقہ رائج ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جہاز پر مال چڑھا دینے کے بعد اصل بائع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا۔ پھر یہ مشتری مال کی وصولی سے پہلے، جب کہ مال ابھی سمندر میں ہوتا ہے، تیسرے شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے اور مال کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا، بلکہ تیسرا شخص ضامن ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں بیع قبل القبض پائی ہے۔ احناف ؒ اور شافعیہ دونوں کے نقطہ نظر کے مطابق تو درست نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ان کے نزدیک بیع پرقبضہ ضروری ہے، بلکہ قبضہ سے بڑھ کر تخلیہ بھی ہونا چاہیے (۱۱) جب کہ مالکیہؒ کے ہاں طعام کے علاوہ سبھی چیزوں کی بیع قبل القبض جائز ہے۔ ( ۱۲) چنانچہ دورحاضر میں اس طرح بہت سے معاملات کثرت سے طے کیے جاتے ہیں۔ اس ناگزیر ضرورت کی بنیاد پر فقہائے احناف ؒ نے بھی مالکیہ کے قول پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔
اسی طرح کی ایک مثال عقدکے اندر جہالت کے اعتبار سے غرر کی ایک صورت عقد العربون( بیعانہ والا معاملہ) ہے یعنی وہ معاملہ جس میں ایک فریق بیعانہ دیتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خریدار بائع کو کچھ رقم اس شرط پر دیتا ہے کہ اگر وہ بعد میں بائع سے مطلوبہ چیز لے لے تو یہ رقم قیمت کا حصہ بن جائے گی، لیکن اگر بعد میں خریدار سے مطلوبہ چیز نہ لے تو وہ رقم بائع کی ہو گی۔ جس طرح یہ معاملہ بیع کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح کا معاملہ اجارہ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اگر مذکورہ صورت پر غور کیاجائے تو اس میں خریدار یا کرایہ دار کو مطلوبہ سامان لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر وہ مطلوبہ سامان لے لے تو اس کی طرف سے دیا ہوا بیعانہ قیمت یا کرایہ کا حصہ بن جاتا ہے، ورنہ کسی عوض کے بغیر بائع یا موجر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس میں بائع یا موجر کو عقد ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ہر حال میں ضروری ہے کہ وہ مطلوبہ سامان خریدار کے حوالے کرے۔ گویا اس میں ایک فریق کی طرف سے عقد لازم ہوتا ہے اور جب کہ دوسرے کی طرف سے لازم نہیں ہوتا بلکہ اسے عقد ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس عقد میں ایک جانب سے غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے نزدیک یہ عقد جائز نہیں ہے جب کہ حنابلہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ عصر حاضرمیں اس کی شدید ضرورت وحاجت ہے کیوں کہ بیعانہ کے بغیر بیع ہونے کی صورت میں خریدار کو خطرہ رہتا ہے کہ بائع کسی دوسری جگہسے زیادہ قیمت ملنے پر اس چیز کو فروخت نہ کر دے۔ بیعانہ لینے کی وجہ سے وہ پابند ہو جاتا ہے اور اس کا عرف اور رواج بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔
ضرورت اور حاجت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عصر حاضر کے اہل علم نے، اسلامی بینکوں اور حساب مرتب کرنے والی تنظیم aaofi نے بھی اسلامی بینکوں کو مرابحہ میں بیعانہ لینے کی اجازت دی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عقد نہ ہونے پر بینک کو دوسری جگہ سامان بیچنے میں اگر کوئی حقیقی نقصان ہوا ہو تو صرف اس حد تک بیعانہ کی رقم اپنے پاس رکھ لے، زائد رقم کلائنٹ کو واپس کردے اور اگر نقصان نہ ہو تو پھر بیعانہ کی ساری رقم واپس کر دے۔ (۱۳)
سی طرح آج کل کی تجارتی زندگی میں ایک صورت یہ بھی رواج پذیر ہے کہ صرف غائب قرض یا غائب مال کو راس المال نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کے علاوہ نقد رقم یا سامان تجارت بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دوکاندار کے پاس نقد رقم بھی ہے ، دکان میں سامان تجارت بھی رکھا ہوا ہے اور کچھ ادھار کھاتے بھی ہیں۔ اس سے کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ ایک سال کے لیے مجھ سے ایک لاکھ روپے لے لیں، اس سے تجارت کریں اور پھر سال بعد جو نفع ہو، اس میں اتنے فیصد مجھے دے دیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں دکاندار کی جانب سے شرکت میں صرف نقد رقم نہیں مل رہی بلکہ سامان تجارت اور ادھار کھاتے بھی شامل ہو رہے ہیں۔ مذکورہ صورت میں نقد رقم اور ادھار کھاتوں کے علاوہ سامان تجارت کو بھی راس المال کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ فقہی ضابطہ میں فقہاء احنافؒ کے نزدیک سامان تجارت کو راس المال بنانا جائز نہیں، لیکن فقہاء مالکیہؒ کے ہاں اس کی اجازت ہے۔ زمانہ کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے یہ ہے کہ بوقت ضرورت مالکیہ کے قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مولانا تھانویؒ کے اس قول کو اختیارکرنے کی وجہ سے عصر حاضر کی بہت سی جدید صورتوں کا حل بھی نکل آتا ہے۔ مثلاً موجودہ زمانے کی تجارت میں اس کا بھی رواج ہے کہ دو یا دو سے زائد تجارتی فرمیں مل کر ایک مشترکہ تجارتی ادارہ بنا لیتی ہیں۔ ایسی شرکت میں سرمایہ صرف نقد نہیں ہوتا بلکہ نقد اور جامد دونوں طرح کے اثاثے ہوتے ہیں۔ مذکورہ قول کی روشنی میں یہ صورت جائز ہو جا ئے گی۔
ڈاکٹر غازی ؒ کے فقہی نظریات کے مطالعہ سے چندامور سمجھ میں آتے ہیں:
۱۔ ضرورت وحاجت کو پیش نظررکھتے ہوئے کسی بھی فقیہ کی رائے کو قبول کرنے لینے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔
۲۔ بعض دفعہ مسائل پر عمل کرتے ہوئے امت کی بہتری اور مصلحت کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔
۳۔پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کی پوری گنجائش موجود ہے۔
اسی طرح ڈاکٹر صاحبؒ کی فقہی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے اجتہادات بدلتے ہوئے حالات اوران کے تقاضوں کے گہرے شعور کی غمازی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں تعلیم و تدریس کا دائرہ بھی مخصوص فقہی نظریات کے علاوہ تمام فقہی نظریات سے آگاہی تک وسیع کیا اجانا چاہیے تاکہ علمی روایت میں ارتقا بھی ہو اور تقاضوں کوکلی طور پر عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب اگرچہ ؒ فقہی توسع و تنوع رکھتے تھے اور اس طرح رہنمائی بھی کرتے رہے، لیکن ایک سوال کے جواب میں انھوں نے بعض ضروری امور کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں:
’’بہتر تو یہ ہے ایک ہی فقیہ کی پیروی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پسند نا پسند سے pick and choose کاکام شروع کر دے تو اس سے شریعت کے مقاصدکو نقصان پہنچنے کا امکان رہے گا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک فقیہ کی رائے کی پیروی کریں۔ لیکن جواہل علم ہیں، انہوں نے نہ پہلے اس کو لازمی سمجھا ہے اور نہ آج سمجھتے ہیں۔ جب فتویٰ دینا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی خاص مسلک کانقطہ نظر اگر زیادہ قوی ہے تو اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔‘‘ (۱۴)
ڈاکٹر صاحب اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ عامۃ الناس کو بالکلیہ مسائل میں اختیار دینے کی بجائے امت کے فقہا کو اپنی صلاحیتوں کو اجتہاد پر لگانا چاہیے اور تاکہ وہ لوگوں کو درپیش مسائل سے نجات دلا سکیں ۔بصورت دیگر ان میں تلفیق عام ہو جائے گی۔ اس کے نتیجہ میں نئے فتنوں کا وجود اور امت میں انتشار کے ساتھ صحابہ کرامؓ ، ائمہ عظام ؒ ، اور سلف صالحین سے بد اعتمادی پیدا ہو گی جو کسی بھی طرح اسلامی معاشرہ کے لیے مفید نہیں ہے۔
حواشی و حوالہ جات
۱۔ سعید احمد اکبر آبادی: اے تو مجموعہ خوبی بچہ نامت خوانم ، مرتبہ سید محمد ازہر شاہ قیصر،(دیوبند، ۱۹۵۵ء )، باب ۶،درحیات انور، ص۱۶۵
۲۔ عبدالرشید ارشد: بیس بڑے مسلمان، ( مکتبہ رشیدیہ، لاہور، ۱۹۷۱ء)، ص۳۷۷
۳۔ قاضی افضل حق قرشی:اقبال کے ممدوح علماء، (مکتبہ محمودیہ، لاہو، ۱۹۷۸ء ) ص۵۰
۴۔ غازی، ڈاکٹر محموداحمد: محاضرات فقہ ،(الفیصل ناشران کتب ، لاہور، ۲۰۰۵ء) ، ص ۵۲۵
۵۔ المرجع السابق، ص۵۳۴
۶۔ المرجع السابق، ص۵۳۸
۷۔ المرجع السابق، ص۵۳۸
۸۔ االمرغینانی ، برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر ، الہدایہ،( ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراتشی، ۱۴۱۷ھ)،باب بیع الفاسد ،فصل فیما یکرہ)،ص ۵؍ ۱۴۴
۹۔ عینی ،بدرالدین ،ابومحمد محمود بن احمد، عمدۃ القاری، (دارالفکر بیروت، لبنان) کتاب الاجارۃ، با ب اجر السمسرۃ، ۱۲؍۹۳
۱۰۔ محمد بن علی بن محمدالملقب بعلاء الدین (م۱۰۸۸ھ)،الدر المختار، ( ایچ ایم سعید کمپنی ،کراچی، ص)۶؍ ۶۳
* اشرف علی تھانوی، امداد الفتاویٰ ، (مکتبہ دارالعلوم کراچی، پاکستان)ص۳؍ ۳۶۶
۱۱۔ ابن عابدین، محمد بن امین الشامی، رد المحتار، (ایچ، ایم سعید، کراتشی، ۱۴۰۶ھ)،ص ۴؍ ۱۸۲
۱۲۔ ابن رشد ، ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد :بدایۃ المجتہد، ( مطبعہ محمد علی صبیح، مصر، ۱۹۹۹ء)، ۲؍ ۱۴۴
۱۳۔ اعجاز احمد صمدانی، ڈاکٹر:اسلامی بینکاری اور غرر، (ادارہ اسلامیات ، کراچی،۲۰۰۶ء )،ص۴۴۔۴۵
۱۴۔ محاضرات فقہ، ۵۱۰
آتشِ رفتہ کا سراغ
پروفیسر محمد اسلم اعوان
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی کتاب ’’مسلمانوں کا دینی وعصری نظام تعلیم‘‘ پڑھتے ہوئے اسلام کی نشاۃ ثانیہ، برصغیر میں اسلامی فکری تحریکوں کے احیا اور عظمت رفتہ کے حصول کے لیے مصنف کا مبنی بر اخلاص جذبہ دیکھ کر بے اختیار علامہ اقبالؒ کا یہ شعر مسلسل ذہن وفکر میں گونجتا رہا:
میں کہ مری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ
میری تمام جستجو، کھوئے ہوؤں کی آرزو
فاضل مصنف نے تاریخ، شعور، حقائق، جذبات اور احساسات کی روشنی میں گم شدہ عظمتوں کے احیا کا سراغ لگانے کے لیے معروضی صورت حال سے آگاہی کے بعد جس ژرف نگاہی سے مسائل کی نشان دہی کی ہے، اس سے ماہر معالج کی حذاقت یاد آجاتی ہے ، بقول اقبال :
مردان کار ڈھونڈھ کے اسباب حادثات
کرتے ہیں چارۂ ستم چرخ لاجورد
اصل میں مصنف کے ذہن وفکرکا قابل رشک پہلو یہ ہے کہ وہ دین اسلام اور اس کے تہذیبی وتمدنی اور سیاسی تفوق پر جس خود اعتمادی سے اظہار خیال کرتے ہیں، ایسی خود اعتمادی بہت کم اہل نظر کے ہاں دیکھنے میں آتی ہے۔ آج اکیسویں صدی کے پہلے عشرے میں یہ تلخ حقیقت نظر آ رہی ہے کہ علوم جدید کے حامل مسلمان چند ایک استثنائی صورتوں کے علاوہ، نہ صرف یورپ سے فکری طور پر مرعوب ہیں بلکہ انگریزوں سے بڑھ کر انگریزہیں۔ بقول اقبال :
نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو
ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے
’’ دینی مدارس: مفروضے، حقائق، لائحہ عمل‘‘ کے زیر عنوان برصغیر پاکستان، ہند اور بنگلہ دیش میں دینی مدارس کے عظیم کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ ان مدارس نے ’’ ملک وملت کی پوری تاریخ میں بالعموم اور انگریز کی دوسو سالہ تاریخ میں بالخصوص یہاں اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا تحفظ کیا۔‘‘ (ص ۲۲) محمود احمد غازیؒ کے ان الفاظ کو پڑ ھ کر سرسر ی طور پر نہ گزر جائیے گا۔ اس کے پس منظر میں دینی مدارس سے وابستہ، اسلام اور علوم اسلامیہ سے وابستہ ہزاروں معلمین اور تلامذہ کی جاں سوزی اور پوری دنیا کو اختیاری طورپر تج کر مقہوری کی سطح پر رہ کر ایثارو فدا ہونے والوں کی لاتعداد روشن مثالیں ہیں۔ ان گم نام قربانیوں کے باعث آج بھی دینی مدارس روشن میناروں کی طرح بلند وبالا اور قائم ودائم کھڑے عظمت ونور بکھیر رہے ہیں۔
یہاں مجھے سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ (م ۱۹۶۱ء) کے قریبی ساتھیوں میں ایک نمایاں نیاز مند اور رفیق قاضی احسان اللہ شجاع آبادی ( م ۱۹۶۷ء) کا واقعہ یا د آ رہا ہے۔ شجاع آباد میں قیام پاکستان سے قبل برطانوی حکومت کے عروج کے دور میں ایک سول جج تعینا ت تھے ۔ یہ جج صاحب مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے سبب نسلی طورپر مسلمان تھے، لیکن جذباتی طور پراسلام سے وابستگی کے باوجود دین اسلام سے رواجی تعلق رکھتے تھے۔ اس دور کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان طبقے کی اکثریت کے ذہن یورپ سے فکری طور پر مرعوب تھے اور مسلمانوں کے تہذیبی اور علمی ورثے کے بارے میں کچھ قابل رشک خیالات نہیں رکھتے تھے، بلکہ انگریزی تعلیم کے حصول اور انگریزی استادوں کے زیر اثر مسلمانوں کے ماضی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار اور علما سے بھی نالاں اور گریزاں رہتے۔ ہوا یوں کہ اتفاق سے جج صاحب کی بیٹی ایم اے فارسی کرنے کے لیے پرائیویٹ طور پر تیار ی کے لیے فارسی کے کسی معلم ٹیوٹر کی رہنمائی اور امداد کی خواہاں تھی۔ جج صاحب تو فارسی سے ناخواندہ محض تھے، ان کی نظر انتخاب ٹیوٹر کے طور پر قاضی احسان احمد پر جا ٹھہری ۔ مجبوراً قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بچی کے لیے فارسی زبان کی تدریس کی درخواست کے ساتھ فیس کی پیش کش بھی کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا، فیس اور ٹیوشن دے کر نہ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے اور نہ ہم نے معاوضہ لے کر کسی کو پڑھایاہے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، میں اسے بلامعاوضہ فارسی پڑھا ؤں گا۔ قصہ مختصر، وہ طالبہ قاضی صاحب کے پاس کم وبیش ایک سال تک فارسی پڑھتی رہی۔ یونیورسٹی کے امتحان میں اس طالبہ نے ایم اے فارسی میں سب سے اول پوزیشن حاصل کی۔ جج صاحب یہ خوش خبری سن کر جہاں انتہائی شاداں وفرحاں ہوئے، وہاں قاضی صاحب کی فارسی میں مہارت دیکھ کر علماء کرام کے علم وفضل اور مرتبہ ودرجہ کے بارے میں اپنے سابقہ احساسات سے رجوع کرتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ خود چل کر قاضی صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قاضی صاحب! آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا: ’’ میری تعلیم اتنی ہے کہ مجھے کوئی پانچ روپے ماہانہ نوکری دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔‘‘
کہنے کو تو یہ ایک سرسری واقعہ ہے، لیکن گزشتہ دو سو سال میں دیسی انگریزوں نے دینی مدارس کے تعلیم یافتہ حضرات کو رزق کی مار دینے کی جو مذموم کوششیں یعنی سعی نامشکور کی، اس کا نچوڑ اور خلاصہ قاضی صاحب کی بیان کردہ اس مبنی برحقائق حکایت میں بطور المیہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے دینی مدارس کی عظیم تاریخ جس پر محمود احمد غازی نے اعداد وشمار کی روشنی میں اظہار خیال کیا ہے۔
دینی مدارس کے عظیم کردار کو اکیسویں صدی کے جدید دور اور آئندہ مستقبل میں جدید تعلیم سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور آج سے تقریباً سوا صدی قبل دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قیام کو اس جدوجہد کی پہلی جست کہا جا سکتا ہے۔ فاضل مصنف اس سلسلے میں اپنی دردمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں :
’’ دور جدید ایک پیچیدہ دور ہے۔ اس دور کے ادارے، تصورات اوراس دور کے معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس کے لیے بڑی خصوصی مہارتیں درکار ہیں۔ جہاں فنی مہارتیں ہیں، وہاں بدقسمتی سے شریعت کا علم نہیں ہے اور جہاں شریعت کا علم ہے، وہاں جدید فنی مہارتیں نہیں ہیں۔ ہم پر فرض کفایہ ہے کہ ہم شریعت کے ایسے متعمق ماہرین پیدا کریں جو دینی ماحول، دینی تربیت اور دینی ذوق ومزاج کے ساتھ ساتھ دور جدید کے معیار کی فنی مہارت رکھتے ہوں۔‘‘
محمود احمدغازی نے جس اہم مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بلاشبہ ہماری تہذیبی، تمد نی اور دینی بقا کے لیے اولین ترجیحات میں سرفہرست ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ المیہ اور یہ شتر گربگی بھی برطانیہ کے دو سو سالہ دور غلامی کے ثمرات بد میں سے ہے اور شجر خبیثہ کی طرح مسلسل اپنے برگ وبار چھوڑ رہا ہے۔ قبل ازیں یہ صورتحال نہ تھی۔ اس بارے میں فاضل مصنف بالکل صحیح اور برمحل کہتے ہیں:
’’ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں دینی مدارس اور غیردینی مدارس کی تفریق نہیں تھی۔مجدد الف ثانیؒ ( م ۱۶۲۴ء) اور سلطنت مغلیہ کے وزیر اعظم نواب سعداللہ اور تاج محل آگرہ اور دوسری عظیم الشان عمارتوں کے معمار بھی انھی درس گاہوں کے پڑھے ہوئے تھے۔‘‘
وطن عزیز پاکستان میں عمرانی علوم خصوصاً تاریخ، فلسفہ، عمرانیات، اردو، فارسی ،عربی ادبیات سے روگردانی اور اس حوالے سے عدم توجہی پر مبنی حقارت کا رویہ اور ایسے رجحانات میں روز افزوں کثرت، یہ ایسے تعلیمی المیوں میں سے ہے جن کے ارتکاب سے قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں۔ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے :
’’ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں، امام ابن تیمیہ نے السیاسیۃ الشرعیہ میں لکھا ہے کہ ایسی تمام مہارتوں اور تخصصات کا حاصل کرنا مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے جس کے نہ ہونے کہ وجہ سے مسلمان غیر مسلموں کے محتاج بن کر رہیں۔ اس دور میں فقہ پڑھ کر قاضی بن جاتا تھا، مفتی بن جاتا تھا، گورنر بن جاتا تھا۔ امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ طلبہ فقہ تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن طب، ہندسہ (انجینئرنگ ) کوئی نہیں پڑھتا۔ اس زمانے میں الٹ تھا ۔ آج کل لوگ میڈیکل اور انجینئرنگ تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن فقہ نہیں پڑھتے۔‘‘
علوم جدید کے حصول اور ان میں اعلیٰ مہارت پیدا کرنے کے بعدان کے منفی پہلوؤں کی نشان دہی جس دلیری اور مہارت سے مسلمانوں کی نابغہ روزگار علمی شخصیات نے کی ہے، اس کی نظیر شاید ہی مل سکے۔ چنانچہ زیر نظرکتاب میں اس کی شہادتیں جا بجا بکھر ہوئی نظر آتی ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں:
’’یونانی علوم وفنون کو سیکھ کر ہی ہم اس کا جائزہ لے سکیں گے کہ ان میں کون سی چیز غلط ہے اور کیا چیز ہمارے لیے اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی حجۃ اللہ البالغہ برصغیر کی بہترین مستند تصنیف ہے۔ برصغیر میں اس سے بہتر کتاب اسلام کے فلسفے پر لکھی ہی نہیں گئی۔ وہ بھی ساری کی ساری یونانی علوم وفلاسفہ کی اصطلاحات سے بھر پور ہے۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوگا کہ وہ چیز جو پہلے خطرہ سمجھی گئی، وہ بعد میں خادم بن گئی۔ اسلام خادم بننے کے لیے نہیں آیا، مخدوم بننے کے لیے آیا ہے۔ اگر امام غزالیؒ اپنے دور میں منطق کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ: من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم اصلاً، جس آدمی نے منطق نہیں سیکھی، اس کا علم میں کوئی مقام اور وزن نہیں، اس لیے کہ اس دور میں اہمیت منطق کی تھی۔ اس طر ح آج کے دور میں اگر کچھ دوسرے علوم وفنون، انگریزی زبان، معاشیات، ریاضی، کمپیوٹر کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے تو علماء کرام کو آگے بڑھ کر امام غزالی کی طرح اس کا ادراک کرنا چاہیے۔‘‘
دیار مغرب (یورپ) میں جدید تعلیم یافتہ انگریز، فرانسیسی اور امریکی لوگوں میں سے غیر متعصب اور فراخ دل صاحب مطالعہ لوگ آخر کا راسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر ملت اسلامیہ کے فرد بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے برصغیر پاک وہند اور بنگلہ دیش سے برآمد شدہ نیم خواندہ اور فرقہ پرست امام مسجدوں کی یورپ میں موجودگی یورپ میں فروغ اسلام کے سلسلے میں نہ صرف سوالیہ نشان ہے بلکہ تبلیغ اسلام کے راستے میں بھی ایک بڑی رکاوٹ بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی نشان دہی ملاحظہ ہو:
’’لندن میں یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، یہ بنگالیوں کی، یہ ترکوں کی۔ کیا صحابہ کرامؓ، تابعین ؒ جہاں گئے تھے، انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ یہ بنو ہاشم کی مسجد ہے، یہ خزرج کی ہے اور یہ اوس کی ہے؟ وہاں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہماری اس کمزوری کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم طالب علم کو اس اہم اور بھاری ذمہ داری کے لیے تیار نہیں کر رہے کہ وہ ایسے غیر مسلم اور ناملائم ماحول میں حکمت کے ساتھ دین کی تعلیم پیش کر سکے۔‘‘
گزشتہ دوصدیوں میں یورپی استعمار نے نہ صرف براعظم ایشیا بلکہ براعظم افریقہ کے اکثر مسلم ممالک کو عسکری طور پر اپنے مقبوضات میں شامل کیا اور امت مسلمہ کو دینی، تہذیبی، ثقافتی اور علمی لحاظ سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، لیکن یہ شرف برصغیر پاکستان وہند اور بنگلہ دیش کی سرزمین کو حاصل ہے کہ یہاں علما نے انگریز کے دو سو سالہ قبضہ کے باوجود مسلمانوں کی دینی وعلمی شناخت کو برقرار رکھا۔ محمود احمد غازی کے الفاظ میں :
’’الجزائر میں فرانسیسی استعمار نے اس مقبوضہ ملک کو اپنے رنگ میں رنگ دیا کہ فرانسیسیوں کے جانے کے بعد وہاں عربی بولنے اور لکھنے والے افراد کا وجود ختم ہو گیا۔ اس کے برعکس برصغیر کے علماء کرام، اہل علم، دینی مدارس نے قدیم تعلیمی روایت کے بہت سے پہلوؤں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کو باقی رکھا۔ اس کے بعد جب منتقلی (ٹرانزیشن) کا آخری مرحلہ شروع ہوا، جب استعمار یہاں سے گیااور اقتدار مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں آیاتو اس منتقلی کے وہ خطرناک اور منفی نتائج یہاں پیدا نہیں ہوئے جو کئی دوسرے مسلم ممالک میں پیدا ہوئے۔ صحابہ کرامؓ کی برکات، نفوس قدسیہ، صحابیوںؓ کی برصغیر میںآمد اور ان کے بابرکت قدموں کی کرامت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ان کے ورود مسعود کی مہک سے ان علاقوں کی فضائیں آج بھی پانچ وقتہ اذانوں سے گونج رہی ہیں اور وہاں دینی مدارس، قرآن وحدیث کی تعلیم وتدریس کا سلسلہ جاری وساری ہے۔ ‘‘
عموماً عبارت یا تقریر میں واقعہ لکھنے یا سنانے کے بعد حسب حال شعر لکھنا یاپڑھا جا تا ہے، لیکن میں محموداحمدغازیؒ کی زبانی وہ صورتحال قارئین کے سامنے پیش کرنے سے پہلے تقدیم کے طور پر شعر لکھتا ہوں:
کھلے ہوئے ہیں وہیں پھول سے نقوش قدم
جہاں سے قافلہ گزرا ہے میرے پیاروں کا
محمود احمدغازی کے الفاظ ہیں:
’’لیکن ایک بات نہایت عجیب ہے کہ وہ علاقہ جو صحابہ کرامؓ کے زمانے میں فتح ہواتھا ( اور صحابہ کرامؓ کا دور محدثین کے مطابق ۱۰۰ء تک ہے) وہ آج بھی پاکستان میں شامل ہے۔‘‘
دینی تعلیم وتدریس اسلامی ثقافت کی روح ہے اور یہ ایک ایسی ابدی حقیقت ہے کہ معیار ہمیشہ مقدار پر تفوق رکھتا ہے۔ دینی تعلیم کے فرو غ سے جو کلچر اور تمدن فروغ پاتا ہے، اس نے امت مسلمہ کو ہمیشہ غالب وبرتر رکھا۔ مقام تاسف کہ آج طبقاتی اور دینی اور انگریزی تعلیم کی تفریق وتقسیم سے وہ علمی ودینی ماحول دنیا کی غالب اکثریت کی آنکھوں سے اوجھل ہے او رانسان ہے کہ ہمیشہ سے محسوسات کا رسیا ہے اور موجود وحاضر صورت حال سے متاثر ومرعوب ہوتا آیا ہے۔ مصنف اس صورت حال کو مختصر اور معروضی انداز میں بیان کرتے ہیں:
’’مسلم کمیونٹی (برصغیر) میں، جو عددی اعتبار سے اقلیت میں تھی، جو عسکری اعتبار سے دوسری غیر اسلامی قوتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور تھی، جو تہذیب وتمدن کے اعتبار سے یہاں کی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن صرف اور صرف تعلیم وتربیت کے اس نظام نے جو ۹۲ھ کے آغاز میں مسلمانوں نے قائم کیاتھا، مسلمانوں کو بارہ سو برس تک باقی رکھا۔‘‘
اسلامیان برصغیر پاکستان وہند اوربنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ اسلامیان عالم کا دینی وفکری سرچشمہ سرزمین عرب ہے۔ ۹۲ھ بمطابق ۷۱۲ء میں محمدبن قاسم کی آمد کے وقت سند ھ اور ملتان تک کی زمین عربوں کے ورود سے آشنا ہوئی، لیکن بعد میں کچھ سیاسی، عصری اور دیگر وجوہ کے سبب عرب فاتحین اپنے ان مفتوحہ علاقوں سے رابطہ نہ رکھ سکے اور پھر کافی عرصہ یعنی دو صدیاں گزرنے کے بعد عرب سے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ رکنے کے باعث برصغیر کا شمال میں واقع مسلمان ریاستوں افغانستان، وسط ایشیا، ترکستان سے اس طرح تعلق قائم ہوتا ہے کہ شمال سے سلطان محمود غزنویؒ (۹۹۸ء تا ۱۰۳۰ء) اور اس کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری کی ۱۱۹۳ء میں آمداور دیگر مسلمان فاتحین، مبلغین، علماء کرام، صوفیاء کرام برصغیر کے شمال سے ہندوستان میں وارد ہوتے ہیں اور اسلامیان ہند کا رابطہ عرب کے مسلمانوں سے کٹ کر شمالی علاقوں کے مسلمانوں سے قائم ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اس صورت حال کو کمال تاریخی بصیرت سے بیان کیا ہے:
’’ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلیمی اور فکری رشتہ عرب اور عراق اورعربی بولنے والوں سے کٹ کر ایران اور سنٹرل ایشیا کے ممالک سے قائم ہو جاتا ہے۔‘‘
برصغیر پاک وہند اوربنگلہ دیش میں برطانیہ کی دو سو سالہ غلامی کے بعد آج اکیسویں صدی میں برطانیہ کے پیدا کیے ہوئے ذہنی غلاموں اور دیسی انگریزوں کے ہاتھوں تعلیم وتعلم کی جو درگت بن رہی ہے، اس کا خیال شاید لارڈ میکالے اوراس کے انگریز جانشینوں کو بھی نہ آیا ہوگا۔ بقول اقبالؒ
گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے
کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری
آئے دن کمیشن قائم ہو تے ہیں، تجاویز پر مبنی طول طویل مقالے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، بھاری بھر کم کتابوں پر مبنی رپورٹیں کئی کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتابوں کی صورت میں شائع ہوتی ہیں، لیکن ملی تعلیم نظر انداز کرنے کے مسلسل رویے کے سبب انگریزی تعلیم وتعلم کاسلسلہ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتاہے۔ اگر ان انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں انگریزی کے ایسے فاضل تیار ہوتے جو اقوام یورپ کے سامنے مسلمانوں کانقطہ نظر اور نصب العین خود اعتمادی سے پیش کرنے کے اہل ہوتے تو پھر بھی غنیمت تھا۔ کم از کم ہمیں یہ تو اطمینان ہوتا کہ انگلش میڈیم اسکولوں اور کالجوں میں وہ مسلمان طبقہ تیار ہو رہا ہے جو مغرب کے سامنے اسلامی تہذیب وتمدن کو پیش کرنے کا اہل ہے، لیکن مقام صد افسوس کہ انگلش میڈیم اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والا طبقہ دینی علوم، مشرقی ادبیات، عربی، فارسی، اردو سے کلی طور پر ناآشنا ہے اور اپنے ملی اور ادبی ورثہ سے حقار ت کارویہ رکھتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ گزشتہ کئی عشروں سے انگریزی زبان وتہذیب سے عاشقانہ اور والہانہ انداز رکھنے کے باوجود اپنی محبوب ومرغوب زبان وتہذیب یعنی انگریزی زبان وادب سے اتنی بھی آگاہی نہیں رکھتا کہ اس پرعلمی اندازمیں اظہار خیال کرسکے۔ یعنی وہ صرف اور صرف لارڈ میکالے کے مجوزہ کلر ک بن کر نسل درنسل کالے اور دیسی انگریزوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بقول اکبر الہ آبادی ؒ :
چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا
شیخ ومسجد سے تعلق ترک کر، اسکول جا
چار دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ
کھا ڈبل روٹی، کلرکی کر، خوشی سے پھول جا
مقام ماتم کہ آج کا برسر اقتدار حکمران طبقہ اور تعلیم، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی تشکیل کا اختیار رکھنے والا مقتدر گروہ کچھ ایسے نادیدہ عاشق کی طرح انگریزی کی زلف گرہ گیرکا اسیر ہے کہ وہ اسلامی ودینی ثقافت کے فکری سرچشموں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ادھر کا رخ کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ اسی مذکورہ بالا درس نظامی نے اپنے زمانے کے عبقری لوگ پید اکیے ہیں۔ محمود احمد غازیؒ کی زبانی:
’’درس نظامی محض دینی تعلیم کا نظام نہیں تھا۔ .....یہ تو اس زمانے کے حساب سے ایک ماڈرن اور اپ ٹوڈیٹ نظام کا خاکہ تھا جو اس زمانے کے ایک صاحب علم نے وضع کیا تھا۔ .....ملا نظام الدین نے اس زمانے میں جتنے علوم مروج تھے جن کا اندازہ ۵۶کے قریب لگایا جاتا ہے، ان سب کو یکجا کر کے ایک ایسے آٹھ سالہ نظام تعلیم کا خاکہ پیش کیاجس کو آج کل گریجویشن کی ڈگری کے برابر قراردے سکتے ہیں۔‘‘
کسی بھی نظام تعلیم کے روز افزوں فروغ اور نشوونما میں سب سے نمایاں کردار حکومت کی سرپرستی کا ہوتا ہے۔ حکام وقت جس بات کو بھی اختیار کریں، وہ عوام الناس کے لیے وجہ تقلید اور اسٹیٹس (status) کا معیار بن جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سیاح ابن بطوطہ نے اس سلسلے میں ایک بڑی ہوش ر با شہادت دی ہے جس کو محمود غازیؒ نے بایں الفاظ بیان کیا ہے:
’’دہلی کے اجڑنے کے بعد بھی ایک ہزار مدارس اس اجڑے دیار میں موجود تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق محمد تغلق دستر خوان پر اس وقت تک نہیں بیٹھتا تھاجب تک کم ازکم چار سو علما وفقہا اس کے دسترخوان پرموجود نہ ہوں۔‘‘ (ص ۵۶)
محمود غازیؒ کی کتاب پر تبصرہ کا خاتمہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم موجودہ اور آئندہ کے لیے تعلیمی ضابطہ اخلاق کی تجدید کریں۔ پر وفیسرایم عمر الدین (شعبہ فلسفہ، مسلم یونیورسٹی،علی گڑھ) نے امام غزالی کے فلسفہ اخلاق پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے :
"Knowledge of God includes the knowledge of the creator and the creation comprising the universe, the soul, the circumstances attending after death and so on. And knowledge of these things constitue the knowledge of Islam. Thus it is all-comprehending, for every science is a religious science if it promotes the realization of perfection. No science is bad in it self, because every science is simply knowledge of the facts as they are and this can not be bad in intself". (The Ethical Philosophy of Ghazali, Sh. M. Ashraf, Lahore 1977, page 113)
مراد یہ ہے کہ ہرعلم کا حصول دین کا حصہ تھا اور یہ علم حیات ہی کے ہر شعبہ سے متعلق نہ تھا، حیات بعد الممات سے بھی مربوط تھا۔ چنانچہ علم حاصل کرنا اور علم کو عام کرنا ثواب اور سر بسر عبادت ہے۔ یہی عبادت ہے کہ ہر پڑھا لکھا مسلمان دوسروں کو پڑھانا لکھانا اپنے لیے باعث رحمت جانتا تھا ۔ وہ گھر میں بھی معلم ہوتا تھا اور باہر بھی۔ نور کا اکتساب اور نور کی تقسیم، کار خیر میں امداد باہمی ہے۔ چنانچہ معلم کا مقام مسلم معاشرے میں بہت وقیع تھا۔ پہلی بار باتنخواہ اساتذہ بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی میں مقرر کیے گئے۔ یہ یونیورسٹی پانچویں صدیں ہجری میں نظام الملک طوسی نے قائم کی تھی۔ باتنخواہ اساتذہ کا تقرر مسلمان اہل علم کوسخت ناگوار گزرا۔ ڈاکٹر محمد اسد طلس لکھتے ہیں کہ جب ہمہ وقتی تنخواہ دار اساتذہ ملازم ہوئے تو علماء خراسان نے ماتم علم کی مجلسیں منعقد کیں اور کہا کہ :
’’معلمی بلند نظر اور پاک نفس لوگوں کا شیوہ تھا جن کے پیش نظرعلم کے ذریعے کمال وفضیلت کا حصول ہوتا تھا۔ مگر ا ب جو علما آئیں گے، وہ علم کو محض کمائی کا ذریعہ بنائیں گے اور تنخواہ کے خیال سے دوں نہاد اور نکمے افراد بھی اس جانب کا رخ کرنے لگیں گے۔‘‘ (التربیۃ والتعلیم فی الاسلام، بیروت، ص ۱۲۴)
قارئین باتمکین!گستاخی معاف، آج ہم انگریزی تعلیم کے نقصانات اور انگریزی تعلیم کے اداروں کو تو بہت رو چکے، لیکن دینی مدارس میں بھی قابل اساتذہ کے بجائے صاحبزادگان کا قبضہ اور ان دینی مدارس کو جو ہر قابل (merit) کے حامل فاضل اساتذہ کے سپر د کرنے کے بجائے مدارس میں نسل در نسل گدی نشینی کا سلسلہ، یہ صورت حال ہماری دینی تعلیم اور دینی تعلیمی اداروں کے مستقبل کے لیے کوئی نیک فال نہیں ہے۔
اسلام کے سیاسی اور تہذیبی تصورات ۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے افکار کی روشنی میں
محمد رشید
جدید ترین اور حیران کن ذرائع ابلاغ کی ایجادات اور پھیلاؤ کی وجہ سے اکیسویں صدی کو اگر ذرائع ابلاغ و اطلاعات یعنی Information Technology کی صدی کا نام دیاجائے تو غلط نہ ہوگا۔تاہم ذرائع اطلاعات نے جس تیزی اور سرعت سے دہشت ناک حد تک ترقی حاصل کرلی ہے، اس کے برعکس نوع انسانی کو ’’درست اطلاعات‘‘ اور ’’نفع مند معلومات‘‘ پہنچانے والے دنیا میں بے حد کمیاب ہی نہیں بلکہ بے حد کمزور بھی ہیں۔ اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کی دنیامیں جدید ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا استعمال نوع انسانی کو مذہب، اخلاق، حیا اور انسانیت کو مسخ کرنے اور تباہی و بربادی کی آخری حدوں تک پہنچانے میں ہورہا ہے۔ وہ کمیاب لوگ جو نوع انسانی کی بقا، فلاح، اصلاح اور ترقی و خوشحالی کے لیے نوع انسانی کو معلومات و اطلاعات پہنچا سکتے ہیں، ان کی آواز ان جدید ترین ذرائع ابلاغ کے ذریعے نوع انسانی تک پہنچنے ہی نہیں دی جاتی کہ انسانیت علم کے نام پر جہالت، خود فراموشی اور خدا فراموشی کے جس نشے میں مدہوش ہوچکی ہے، کہیں اس کا یہ نشہ ٹوٹ نہ جائے۔ کہیں نوع انسانی ہوش میں نہ آجائے، نوع انسانی کو کہیں اپنی حقیقت، اپنے خالق کی پہچان اور اپنے ابدی انجام سے آگاہی نہ حاصل ہو جائے۔ یہ وہ خوف ہے جو نظام ابلیس کے ایجنٹوں کوہر وقت ستائے رکھتا ہے اور وہ جدید ایجادات کے ذریعہ سے نوع انسانی کو نفس پرستی و ہوس پرستی کے نشے میں مدہوش رکھنے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں صرف کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا نوع انسانی کی حقیقی فلاح و بہبود کے لیے اٹھنے والی کسی بھی طاقتور آواز کو ’’انسان دشمن‘‘ اور ’’تہذیب دشمن‘‘ کا نام دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔
دوسری طرف نوع انسانی کی رہنمائی مذہب کی صاف، سچی اور پاکیزہ تعلیمات کی طرف کرنے والا طبقہ (مذہبی طبقہ) مثبت ’’ابلاغ‘‘ کی قوت سے خوفناک حد تک عاری ہو چکا ہے۔ مشکل، پیچیدہ، اجنبی اور نامانوس انداز تکلم نے جدید دور میں بسنے والے انسان کو مذہبی طبقے سے بہت دور کردیا ہے۔ پھر مذہبی قائدین نہ صرف مثبت ابلاغ کی صفت کے فقدان کا شکار ہیں بلکہ اس طبقہ کی عظیم اکثریت کردار اور اخلاق کے بنیادی ترین جوہری وصف سے بھی اپنے آپ کو عاری کر چکی ہے۔ ان نہایت مایوس کن حالات میں اگر کوئی ایسی دینی شخصیت سامنے آجائے جو حسن کلام، قوت ابلاغ، کردار و اخلاق سے متصف اور جدید و قدیم علوم میں عبوررکھتی ہو، انسانیت کی فلاح و خوشحالی کا واضح شعور رکھتی ہواور ایمان و امن عالم کے کلیدی تصورات پر گہرا یقین رکھتی ہوتونگاہیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ جب ہم نے ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کو آج سے قریباً ایک سال پہلے ان کی تحریروں کے آئینے میں دیکھاتو ہم دنگ رہ گئے۔ ہمیں ایسے لگا جیسے ایک بہت ہی بڑا انسان، قوت ابلاغ کی غیر معمولی صلاحیتوں اور علم وفکرکی بیش بہا دولت سے آراستہ ایک پہاڑ جیسا انسان عام انسانوں میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے۔ اٹھارہ سال تک حصول تعلیم میں منہمک رہنے اور بے شمار مصنفین کے مطالعہ کے باوجود اس عاجز میں کبھی یہ خواہش پیدانہیں ہوئی کہ میں کسی کا شاگرد کہلواؤں۔ گویا زندگی کے چالیس سال مکمل کرنے تک میری یہ محرومی رہی ہے کہ مجھے کبھی یہ شوق اور اشتیاق ہی نہیں ہوا کہ میں کسی کو اپنا استادبناؤں، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ عمر کے چالیسویں سال میں قدم رکھنے والے اس نہایت حقیر راقم کے دل میںیہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش! مجھے علم کے اس پہاڑاور قدرت کے شاہکار، ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی شاگردی اختیار کرنے کا موقع مل جائے۔
جدید دور کے جن مصلحین اور داعیین کی تحریروں کا یہ عاجز مطالعہ کرتا رہا، ان میں مثال کے طور پرسید ابوالحسن ندویؒ ، مولانا منظور نعمانیؒ ، سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ ، مولانا امین احسن اصلاحیؒ ، مولانا تقی امینیؒ ، سید قطب شہید، مولانا وحید الدین خاں، جسٹس تقی عثمانی، ڈاکٹر اسرار احمدمرحوم اور دیگر چھوٹے بڑے بہت سے مصنفین اور مقررین شامل ہیں۔ ان حضرات نے اگرچہ اپنی جگہ متاثر کیا، خاص طور پر سید ابوالحسن ندویؒ کی دردمندتحریروں اور اعتدال پر مبنی تعلیمات نے انتہا پسندی اور تعصب سے بچنے کا خاص سبق دیااور اسلام کے دفاع و ابلاغ میں مولانا مودودیؒ کی بے باک، جری اور سلیس و موثرتحریروں نے بے حد متاثر کیا، لیکن اکیسویں صدی میں جب ڈاکٹر محمود احمد غازی سے ہمیں تعارف حاصل ہوا تو ایسے لگا جیسے پچھلے دو سو سالوں سے مسلمانوں کو ایک ایسے ہی عالم دین کی تلاش تھی جسے ایک طرف قدیم و جدید علوم میں گہری دستگاہ حاصل ہے تو دوسری طرف اسے ایسی قوت ابلاغ حاصل ہے کہ وہ مشکل سے مشکل بات کو بھی نہایت آسان اور سلیس زبان میں بیان کرنے پر عبور رکھتا ہے۔ پھر بھرپور ذہانت، عبقری دماغ، غیر معمولی علمیت، اعلیٰ عہدوں اور اعلیٰ صلاحیتوں نے اس کے قلب پر ذرا بھی منفی اثر نہیں ڈالا۔ وہ عجب و غرور اور فکری کج رویوں سے کوسوں دور سادگی، عاجزی، متانت، اعتدال، حلم اور فکری سلامتی کی دولت سے مالا مال اپنے سفر پر گامزن ہے۔یہ سب خوبیاں دیکھ کر مجھے وہ قدرت کا ایک شاہکار لگا، اکیسویں صدی میں خالق کائنات کا ایک ماسٹر پیس۔ لوگ مادی حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، میں فکری سلامتی، حسن توازن، سلاست و اعتدال اور ابلاغ کی قوتوں سے مالا مال اسلام کے اس معجزے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لیکن خالق کائنات کے اس شاہکار سے ابھی نگاہ و دل پوری طرح سیراب نہیں ہوئے تھے کہ ۲۶ ستمبر کو اطلاع ملی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ (انا للہ و انا الیہ راجعون) اگر یہ بات درست ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں والے کسی جوان آدمی کی موت اس کے بچوں اور بیوہ کے حق میں بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم اس سے کہیں بڑے حادثے کا شکار ہوچکی۔ قدرت نے اس قوم کو ایک شاہکار اور معجزہ نما ہستی سے محروم کردیا،لیکن افسوس کہ کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں۔
جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی
تم چلے ہوتوکوئی روکنے والا بھی نہیں
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا علم انھیں صدیوں زندہ رکھے گا۔ان کی علمی و فکری خدمات کا احاطہ اس مختصر مضمون میں کرنا ممکن نہیں، تاہم ذیل میں ہم ان کی تحریروں سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی فکری سلامتی، شعور کی طاقت اور ابلاغی قوت کا براہ راست مشاہدہ قارئین کرسکیں۔
اسلام کی تاریخ۔۔۔عدل و انصاف کی تاریخ
ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃاللہ علیہ امید اور روشنی کے داعی ہیں۔ چنانچہ شریعت کے اوصاف پر بات کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:
’’شریعت کا چھٹا امتیازی وصف ثبات اور تغیر کے درمیان توازن اور امتزاج ہے۔ جہاں یہ شریعت ایک دائمی شریعت ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے اور جب تک روئے زمین پر یا روئے زمین سے باہر انسان آباد ہیں، شریعت ان کے لیے دائمی نظام حیات رہے گی، وہاں اس شریعت میں نئے نئے حالات اور نئے نئے مسائل کو سمولینے کی ایک بڑی عجیب و غریب صلاحیت پائی جاتی ہے۔‘‘ (محاضرات شریعت، صفحہ ۳۵)
آگے چل کر لکھتے ہیں:
’’واقعہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے اس اہم اور بنیادی وصف کو دور جدید کے بہت سے متجددین اور مغرب سے متاثر مفکرین نے سمجھنے میں کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے مغرب کے زیر اثر اپنے ماضی کی ہر چیز کو منفی اور حال کی ہر چیز کو مثبت انداز میں دیکھنا شروع کردیا ہے۔ مغرب اپنی قدیم تاریخ سے بیزار، اپنے مذہبی پس منظر سے نالاں اور اپنی تاریخ کے نشیب و فراز کے بارے میں غیر مطمئن ہے، اس لیے وہ اپنے ماضی کی ہر چیز کو ناپسندیدہ اور آنے والی ہر چیز کو پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی تاریخ کا ایک طویل دور جو ایک ہزار سال سے زائد عرصے پر محیط ہے بلکہ ڈیڑھ ہزار سال سے زائد عرصے پر محیط ہے، ظلم و تعدی اور مذہب کے نام پر شدید قسم کے جبر و اکراہ سے عبارت ہے۔ مغرب کو اس ظلم و تعدی اور جبر واکراہ سے نکلنے میں بہت محنت کرنی پڑی ہے، یہاں تک کہ خود مذہب کو نظر انداز کرنا پڑا۔ مذہب کے تمام مظاہر کو منفی قرار دے کر ان سے جان چھڑائے بغیر اس ظالمانہ نظام سے بچ نکلنا اہل مغرب کے لیے شاید آسان نہ تھا۔ اس لیے مغرب کی نظر میں، مغرب کی نفسیات میں مغرب کا مذہبی ماضی ایک انتہائی منفی اور ناپسندیدہ ڈراؤنے خواب سے عبارت ہے، جبکہ حال اور مستقبل ایک مسلسل خوش آئند و خوشگوار صورتحال کی نوید دیتا ہے۔ اس لیے مغرب نے ماضی کی کسی چیز سے، خاص طور پر اگر اس کا تعلق مذہب سے ہو، تعلق برقرار رکھنااپنے اس نفسیاتی رجحان اور ساخت کی وجہ سے غیر ضروری سمجھا۔
ہمارے بہت سے مصنفین مغرب کے اس مخصوص پس منظر کا ادراک کیے بغیر اسلامی تاریخ پر بھی یہی تصورات منطبق کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح اسلام کی تاریخ کے تسلسل، شریعت کی اساس اور مسلمانوں کے دین کے نظام اور ثوابت کو متاثر و مجروح کردیتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی تاریخ اسلام سے انحراف کی تاریخ نہیں، بحیثیت مجموعی اسلام پر کاربند رہنے کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کے انسانیت پر مظالم اور ظلم و زیادتی کی تاریخ نہیں، بلکہ انسانیت کے یے ایک خوش آیند نوید کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کی تاریخ عدل و انصاف اور تہذیب و تمدن میں نئی نئی مثالیں قائم کرنے کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو دہرانے کی، اس کو زندہ کرنے کی اور دور جدید میں ایک نئے انداز سے اس کو جنم دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے جان چھڑانا، اسے نظر انداز کرنا اور اس کو منفی انداز میں سمجھنا ایک بدترین قسم کی کم فہمی بھی ہے، مسلمانوں کے مستقبل سے مایوسی کی غماز بھی ہے اور مسلمانوں کے ماضی سے بے خبر ہونے کی دلیل بھی ہے۔‘‘ (محاضرات شریعت صفحہ ۳۷، ۳۸)
شریعت کی بنیاد: علم و عدل
شریعت کی بنیاد کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’شریعت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے: ایک علم، دوسرے عدل۔ شریعت کا بنیادی مقصد، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں واضح طور پر آیا ہے، حقیقی عدل و انصاف کا قیام ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَہُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیْزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ’’اوربلا شک و شبہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر اسی لیے بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب الٰہی اور میزان اسی لیے اتاری کہ لوگ حقیقی عدل و انصاف پر قائم ہوجائیں۔‘‘ گویا قرآن پاک کی رو سے یہ تمام آسمانی کتابوں کا مقصد اولین اور ہدف اساسی رہا ہے کہ انسانی معاشرے میں حقیقی عدل و انصاف قائم ہوجائے، مکمل عدل و انصاف قائم ہوجائے۔ مکمل عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ معاشرے میں علم اور شعور کی سطح موجود ہو۔اگر علوم اور شعور کی سطح معاشرے میں مطلوب درجے کی نہ ہوتو پھر اس معاشرے میں مکمل عدل و انصاف قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔
قرآن کی رو سے انسان خلافت الہٰیہ کا حامل ہے۔ خلافت الہٰیہ کا حامل ہونے کی صلاحیت اس میں علم کی وجہ سے پیدا ہوئی، جیسا کہ قصہ آدم سے واضح ہوتا ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء کُلَّہَا۔ لہٰذا علم اور عدل یہ دونوں انسان کے مقصد وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔انسان کی ملائکہ اور دیگر مخلوقات پر برتری انسان کا مقام و مرتبہ اور انسان کی حیثیت علم ہی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو شریعت دی گئی، اس کا سب سے اہم اور اولین مقصد عدل ہے۔گویا آغاز علم اور انتہا عدل ہے۔‘‘ (محاضرات شریعت، صفحہ ۴۷، ۴۸)
’’مشہورمفکراسلام اور فقیہ، محدث اور سیرت نگار علامہ ابن القیم (متوفی ۷۵۱ھ) نے ایک جگہ لکھاہے کہ شریعت کے احکام تمام تر عدل ہیں۔ شریعت سراپا عدل ہے۔ جہاں شریعت ہے، وہاں عدل ہے۔ جہاں عدل ہے، وہاں شریعت ہونی چاہیے اور جہاں عدل نہیں ہے، وہاں شریعت نہیں ہوسکتی۔ بالفاظ دیگر اگر کوئی شخص شریعت کے احکام کی ایسی تعبیرکرتاہے جس کے نتیجے میں عدل قائم نہیں ہوتا تو وہ تعبیر نظر ثانی کی محتاج ہے۔‘‘ (محاضرات شریعت صفحہ ۶۸)
اسلام نے دنیا کو عدل کا نیا اور کامل تصور دیا
عدل کے تصور پر گفتگوکرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’اسلام سے پہلے دنیا عدل کے ایک ہی تصور سے واقف تھی اور یہ وہ عدل تھا جو بادشاہ، حکمران اور بانیان ریاست اپنی رعایا کے درمیان کیا کرتے تھے۔ .....قرآن مجید نے محض اس درجہ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ جہاں حکمرانوں کو انصاف کا حکم دیا ہے، جہاں عدالتوں کو انصاف کرنے کی تلقین کی ہے، وہاں افراد کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے عدل و انصاف کے جو تقاضے قاضی یا حکمران یا ریاست انجام دے گی، اس کی سطح اور ہوگی، جب افراد عدل و انصاف کا فریضہ انجام دیں گے تو ان کی سطح اور ہوگی۔ اس انفرادی عدل کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ افراد سب سے پہلے خود اپنے ساتھ عدل کررہے ہوں، ان کے اپنے مزاج اور رویے میں اعتدال پایاجاتا ہو۔ اعتدال، عدل ہی سے نکلا ہے۔ اعتدال، عدل ہی کی ایک شکل ہے۔ انسان اپنے رویے میں جب توازن پیدا کرے گا، اپنے اندر سے پیدا ہونے والے تقاضوں کے درمیان توازن سے کام لے گا، جسمانی، روحانی، اخلاقی، نفسیاتی، جذباتی، ان تمام تقاضوں کے درمیان اعتدال کے رویے کو اختیار کرے گا، تبھی وہ دوسروں کے ساتھ عدل سے کام لے سکے گا۔‘‘ (محاضرات شریعت صفحہ ۶۹)
حریت وغلامی۔۔۔اسلام اورجدیدمغربی دنیا کا فرق
حریت و غلامی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
’’اسلام نے اگر غلامی کو برداشت کیا تو بعض بین الاقوامی حالات کی وجہ سے برداشت کیا۔...... لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب غلامی کا یہ محدودتصورموجودبھی تھا، سزا کے طور پر غلامی ایک حد تک رائج بھی تھی، اس وقت بھی ان غلاموں کو جو مسلم معاشرے میں رہتے تھے، آج کے ان آزادوں سے بڑھ کر مقام و مرتبہ حاصل تھا جو آج کی نام نہاد آزاد دنیا میں مقیم ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آج آزاددنیا میں بہت سے لوگوں کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ مجھے یہ بات عرض کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ مغربی دنیا میں جدید ترقی یافتہ مہذب دنیا میں اور مغربی تصورات کی علمبردار دنیا میں مسلمانوں کو، اہل اسلام کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو دور اسلام میں غلاموں کو حاصل ہوا کرتے تھے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں کتنے غلام تھے جو فرمانروا بنے، جنہوں نے حکومتیں قائم کیں، جو فاتحین بنے! کتنے غلام ہیں جو صف اول کے علما اور دینی قائدین قرار پائے!......
اسلام کا تصور حریت اتنابلندہے کہ ابھی اس کا ادراک کرنے کے لیے دنیا کو بہت آگے جانا ہے۔ بہت سے نشیب و فراز سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد ہی دنیا کو اندازہ ہوگا کہ جس حریت کی اسلام نے تعلیم دی، وہ کیا مقصود رکھتی ہے، وہ کیا چیز ہے۔‘‘(محاضرات شریعت صفحہ ۷۳، ۷۴-۷۵)
توازن ۔۔۔شریعت کا حسن
توازن کے موضوع پراپنا نقطہ نظر یوں بیان کرتے ہیں:
’’اسلام میں روحانیت اور مادیت کے درمیان، دنیا اور آخرت کے تقاضوں کے درمیان،عقل اور وحی کے درمیان، افراد اور معاشرے کے درمیان، ماضی اور مستقبل کے تقاضوں کے درمیان، ثوابت اور متغیرات کے درمیان، حقائق اور آئیڈیل کے درمیان توازن و اعتدال پایاجاتا ہے۔نہ اسلام نے حقائق اور واقعات کی بنیاد پر اپنے آئیڈیل کو چھوڑا، نہ آئیڈیل اور مثالی صورتحال پر زور دیتے ہوئے واقعات اور حقائق سے صرف نظر کیا۔ اسلام کی تعلیم میں دونوں کے درمیان توازن موجود ہے۔ انسانی کمزوریوں کا احساس بھی ہے، انسان کی پریشانیوں اور مجبوریوں کا اندازہ بھی ہے، چنانچہ شریعت کے احکام میں عزیمت اور رخصت کی جو ترتیب ہے، وہ اسی آئیڈیل اور حقیقت کے درمیان توازن کی ایک جھلک یا توازن کے بہت سے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔‘‘ (محاضرات شریعت صفحہ ۷۶)
عقیدہ کی اہمیت اور مغربی ملحدانہ تہذیب
عقیدہ کی اہمیت ایک منفرد اور اچھوتے انداز سے یوں بیان فرماتے ہیں:
’’کمپیوٹر انسانی عقل کو سامنے رکھ کر بنایاگیا ہے۔ انسانی عقل کمپیوٹر کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی گئی، لیکن چونکہ بعض اوقات مشبہ اور مشبہ بہ میں ترتیب بدل جاتی ہے، اس لیے سمجھانے کی خاطر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عقل ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ لیکن یہ کمپیوٹر جتنا بھی برتر اور پیچیدہ یعنی سوفسٹی کیٹڈ (sophisticated) ہو، جتنا بھی ترقی یافتہ ہو، وہ ایک سوفٹ وئیر (software) کا محتاج ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کمپیوٹر میں غلط سوفٹ ویئر (software) ڈال دیاجائے تو وہ بھی غلط رخ پر کام کرے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ جو softwareاس انسانی کمپیوٹر میں ڈالا جائے، وہ درست ہو۔ چنانچہ عقیدہ ہی وہ سوفٹ وئیر ہے۔
عقیدہ کی تعلیم دینے کا شریعت نے بچپن سے حکم دیا ہے۔ بچپن سے بچے کو یہ بتاؤ کہ اسلام کے عقائد کیا ہیں۔ سات سال کی عمر ہوتو نماز کی تلقین کرنا شروع کردو۔ دس سال کی عمر ہوجائے اور بچہ نماز نہ پڑھے تو جسمانی سزا بھی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے جو محبت تھی، وہ مشہور و معروف ہے، اپنے بچوں سے بھی اور دوسروں کے بچوں سے بھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کی خاطر اور انسانی عقل کو ایک خاص رخ پر ڈالنے کی خاطر جسمانی سزاتک کی اجازت دی ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو ہلکی پھلکی سزا بھی اس کو دے سکتے ہو۔ یہ بات کہ انسانی عقل کو صحیح رخ پر چلایاجائے، اس کو صحیح راستہ بتایا جائے، غلط راستوں پر جانے سے روکا جائے ، اس کی اہمیت کو احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے بیان کیاگیا ہے۔
بعض متجددین، ملحدین اور دور جدید کے دین سے برگشتہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عقیدہ کے نام سے جو تعلیم مسلمانوں کو دی جاتی ہے، یہ ان ڈوکٹری نیشن (indoctrination) ہے۔ indoctrination کا لفظ استعمال کرکے عقیدے کی تعلیم کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مغرب کی لادینی تہذیب بڑے زور و شور سے indoctrination کر رہی ہے۔ مغرب کی آنے والی نسلوں کو جس انداز سے سیکولرازم اور لامذہبی اباحیت کے رخ پر پروگرام کررہی ہے، اس کا ایک ہزارواں حصہ بھی مسلمانوں میں عقیدے کی تعلیم کے لیے نہیں ہورہا ہے۔ یہ بات کہ دوسرے اپنے لامذہب اور ملحدانہ عقائد بچے بچے کے ذہن نشین کردیں، دین اور زندگی کا تعلق منقطع کردیں، اخلاق اور دین کی رہنمائی کو اجتماعی زندگی سے نکال دیں، اس کو تو انڈوکٹری نیشن نہ کہا جائے، لیکن اگر مسلمان بچوں کو یہ بتایاجائے کہ ان کا تعلق اسلام اور مسلمانوں کے گھرانوں سے ہے، وہ قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پاک کے بنیادی عقائد یہ ہیں تو اس کو ان ڈوکٹری نیشن کہہ کر اس کی اہمیت کم کی جائے۔ یہ شاخسانہ دور جدید کے ملحدانہ دور میں ہی ہوسکتا تھا۔ یہ ماضی میں ممکن نہیں تھا، لیکن افسوس بعض ایسے حضرات بھی اس طرح کی باتیں کرتے پائے جاتے ہیں جو اپنا ایک اسلامی اور دینی حوالہ رکھتے ہیں۔‘‘ (ایضاً ص ۹۹)
موجودہ زوال: فکری توازن سے محرومی کا نتیجہ
’’جب تک عقل و نقل کا یہ توازن مسلمانوں میں موجود رہا، جب تک امت مسلمہ میں فکری آزادی، خودمختاری اور قرآن و سنت سے براہ راست وابستگی موجود رہی، اس وقت تک مسلمانوں کا فکری مقام قائد اور رہنما کا رہا۔ جب یہ فکری آزادی کمزور پڑی، جب مسلمان غیروں کی تقلید کا شکار ہوئے تو پہلے ارسطو اور افلاطون کی تقلید شروع ہوئی، پھر ارسطو اور افلاطون کے درجے سے نچلے درجے کے لوگوں کی تقلید شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے جب تقلید پسندی مسلمانوں کے مزاج کا حصہ بن گئی تو ہر کس و ناکس کی تقلید شروع ہوگئی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی مغربی زبان میں کوئی بات لکھ دے یا جس کا تعلق کسی مغربی ملک سے ہو، اس کی بات کو بلا چون و چرا قبول کرلیاجاتا ہے اور تقلید کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ فلاں مغربی شخص نے یہ بات یوں لکھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ مغرب کے گھٹیا سے گھٹیا انسانوں کی تقلید کو باعث فخر سمجھتا ہے اور جو دینی طبقہ ہے، وہ متاخرین کے بھی متاخرین کی تقلید کو کافی سمجھتا ہے اور اس کی نظر میں متاخرین کے متاخرین نے بھی جو لکھ دیا ہے، وہ شریعت کے باب میں حرف آخر ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۱۴۵)
بنیادی حقوق ۔۔۔مسلم تہذیب اورمغربی تہذیب کا فرق
مسلم تہذیب کا مغربی تہذیب سے فرق واضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:
’’اس سے بھی بڑھ کر مسلم معاشرے میں pluralismکی ایک بڑی مثال یہ ہے، کثیر العناصر معاشرہ ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں روزاول سے غیر مسلم باشندوں کو نہ صرف قبول کیاگیا بلکہ ان کو وہ تمام حقوق اور مراعات دی گئیں جو خود مسلمانوں کو حاصل تھیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ مشہور ہے، فقہی لٹریچر میں کثرت سے بیان کیاجاتا ہے کہ ’لہم ما لنا علیہم ما علینا‘۔ جو غیر مسلم دنیائے اسلام کی شہریت اختیار کرتے ہیں، ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں، ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہیں۔ یہ بات مختلف فقہاے اسلام نے مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ مشہور حنفی فقیہ اور فقہ حنفی کے صف اول کے ائمہ اور مجتہدین میں سے ایک حضرت امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ’’المسلم والکافر فی مصائب الدنیا سواء‘‘کہ مسلمان اور کافر دنیوی معاملات میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یعنی ان میں اگر کوئی فرق رکھا جائے گا رویے میں اور معاملات میں تو روز قیامت رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو سزا دینا چاہے گا، وہ دے گا، لیکن اس دنیا کے معاملات میں ، آپس میں لین دین میں، آپس میں جائیداد کے تبادلے میں، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں، ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کے تحفظ میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔
آج مغربی دنیا کے قائدین و مفکرین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان تمام امتیازات کا خاتمہ کردیا ہے جو انسانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ یہ ذرا ان مسلمانوں سے پوچھیں جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں کہ ان کے خلاف کتنے امتیازات ختم ہوگئے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اپنے دین کے مطابق خاندانی معاملات منظم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی جائیداد کو شریعت کے مطابق اپنے وارثوں میں تقسیم نہیں کرسکتے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی روزمرہ کی عبادات کو سہولت سے انجام نہیں دے سکتے۔ آج کتنی مسلمان بچیاں اور خواتین ہیں جن کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس تک پہننے کی اجازت نہیں۔ آج بھی یورپ کے بلکہ یورپ سے متاثر بہت سے ممالک میں سکھوں کو ڈاڑھی رکھنے کی اجازت ہے، مسلمانوں کو نہیں، سکھوں کو پگڑی باندھنے کی اجازت ہے، مسلمانوں کو ٹوپی اوڑھنے کی اجازت نہیں۔
اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کو نہ صرف مکمل آزادی اور مساوات حاصل رہی، بلکہ بعض ایسے حقوق بھی حاصل رہے جو مسلمانو ں کو حاصل نہیں ہیں۔ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض پہلوؤں سے غیر مسلموں کا درجہ اور اسٹیٹس مسلم معاشرے میں مسلمانوں سے بہتر ہے۔ بہت سے معاملات میں ان کو وہ مراعات حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اس کی اجازت بھی دی گئی کہ وہ اپنے شخصی معاملات، اپنے مذہبی معاملات ، اپنے مذہب کے مطابق انجام دیں اور انہی کی عدالتیں، انہی کے قاضی ان کے معاملات کا فیصلہ کریں۔ نہ صرف عہد نبوی میں اور عہد خلفائے راشدین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے مذہبی قائدین ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتے تھے، اپنے مذہبی معاملات کو خود چلاتے تھے، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے دور میں، اس سے پہلے دور سلطنت میں، ان تمام ادوار میں غیر مسلموں کے معاملات، غیر مسلم عدالتیں، ان کے اپنے نظام کے مطابق چلایا کرتی تھیں۔ کثیر العناصر معاشرہ ہونے کی ایسی کوئی مثال آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۱۵۱-۱۵۳)
مغربی دنیا کا المیہ ۔۔۔اخلاق کی بنیادکیا ہو؟
مسلم تہذیب اور مغربی تہذیب کے ایک اور فرق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’مسلمان فقہا اور متکلمین و مفکرین کے ہاں کبھی اخلاق اور روحانیات میں کسی قسم کے باہمی تعارض یا تناقض کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ مکارم اخلاق کی حقیقی اساس کے بارے میں مفکرین اسلام کبھی کسی فکری یا نظریاتی الجھن کا شکار نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس مغربی دنیامیں، قدیم مغربی دنیا ہو یا جدید مغربی دنیا، مشرقی یورپ کی یونانی تہذیب ہو ، وسطی یورپ کی رومن تہذیب ہو یا مغربی یورپ کی حالیہ دنیا ہو، ان سب میں بنیادی سوال جو ہمیشہ زیر بحث رہا ہے، وہ اخلاق کی علمی اور فکری بنیاد کا رہا ہے۔اخلاق کو کس بنیاد پر استوار کیاجائے؟ اس پر مغربی دنیا میں کبھی بھی اتفاق رائے نہیں ہوسکا۔ یونانیوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ دو متضاد رجحانات اور رویوں کے درمیان توازن اور اعتدال کا نام اخلاق ہے۔ عقلی اعتبار سے یہ ایک اچھی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس پر اچھی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں، مضامین لکھے جاسکتے ہیں، لیکن خود توازن اور اعتدال کا تعین کیسے کیاجائے گا اور کس بنیاد پر کیاجائے گا؟ اس کی کوئی طے شدہ حقیقی عقلی اور قطعی بنیاد یونانیوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۱۷۷)
مکارم اخلاق کی اسلام میں اہمیت
ڈاکٹر محمود غازی ؒ مکارم اخلاق پر اپنے اچھوتے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’مکرام اخلاق کچھ لوگوں میں فطری اور طبعی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ مکارم اخلاق جہاں بھی پائے جائیں، وہ قابل تحسین ہیں۔ اسلام کی شریعت نے ان کو پسند کیا ہے، ان کا اعتراف کیا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کا قصہ مشہور ہے۔ ایک جنگ میں جو اس قبیلے کے خلاف لڑی گئی تھی جس سے حاتم طائی کی بیٹی کا تعلق تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی کی جہاں رشتہ داری تھی، اس کے خلاف جنگ ہوئی، دشمنوں کو شکست ہوئی اور میدان جنگ میں جو لوگ موجود تھے، وہ قید کرکے مدینہ منورہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دوسرے دن جنگی قیدیوں میں جو خواتین یا بچے تھے، ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ وہاں ایک خاتون بڑی باوقار معلوم ہوتی تھیں اور لگتا تھا کہ یہ خاتون کسی بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے کہا کہ میں اپنے قبیلہ کے سردار کی بیٹی ہوں، اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرے والد لوگوں کی حمایت کیا کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے، قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، امن و امان قائم رکھنے میں کوشاں رہتے تھے، انہوں نے کبھی کسی سوالی کا سوال نہیں ٹالا۔ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ’’اے لڑکی! یہ تو واقعی مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے اخلاق ہیں‘‘۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’خلوا عنہا‘‘، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ ’’فان اباہا کان یحب مکارم اخلاق وان اللہ یحب مکارم الاخلاق‘‘، اس لڑکی کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ بھی مکارم اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا واقعی اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق کو پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں وہی داخل ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔‘‘ اس سے پتہ چلا کہ مکارم اخلاق جہاں بھی ہوں، وہ قابل تعریف ہیں اور ان کو شریعت پسند کرتی ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۰۱-۲۰۲)
حجاب کا متوازن تصور
ڈاکٹرمحمود احمد غازی ؒ کے ہاں حجاب کا تصور بھی بہت معتدل اور متوازن شکل میں موجود ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:
’’قرآن کے احکام میں حجاب کے مسائل کو تفصیل سے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں کہ مختلف اسلامی ممالک کے مقامی رواجات کو بعینہ شریعت اسلامی سمجھا جانے لگا ہے۔ اگر کسی ملک میں خاص انداز کا پردہ رائج ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ شریعت کے احکام کا لازمی تقاضا ہو۔ وہ رواج بلا شبہ شریعت کے مطابق ہوسکتا ہے، شریعت سے ہم آہنگ ہوسکتا ہے، لیکن ہر وہ رواج جو شریعت کے مطابق ہو اور اسلام کے احکام سے ہم آہنگ ہو، شریعت کی نظر میں لازمی طور پر ہر جگہ اور ہر فرد کے لیے واجب اور فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی رواج ہوسکتا ہے۔ اس لیے مقامی رواجات، شریعت کے احکام، فقہا کے اجتہادات، ان تینوں کے درمیان فرق لازمی ہے۔جہاں تک مقامی رواجات کا تعلق ہے، اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ ان کو اختیار کرے تو وہ ضرور ایسا کرنے کا پورا حق رکھتا ہے اور کسی بھی مطابق اسلام مقامی رواج کو اختیار کرسکتا ہے۔ کسی مشرقی یا مغربی شخص کو کسی بھی بنیاد پر اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہماری افغان بہنیں، افغانستان کی خواتین، ایک خاص انداز کا برقعہ اوڑھتی ہیں تو یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ ان کا مقامی رواج ہے جو صدیوں سے چلا آرہا ہے۔ نام نہاد آزادی کے علمبردار کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس رواج کا مذاق اڑائے، اس پر اعتراض کرے اور اس کو انسانی حقوق اور تہذیب وتمدن کے خلاف قرار دے۔ لیکن دوسری طرف کسی کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ کسی اور ملک کی خواتین جو اس طرز حجاب کو پسند نہیں کرتیں، ان پر زبردستی وہ طرز حجاب مسلط کرے۔ مصر یا ترکی کی خواتین کو مجبور کرے کہ وہ بھی اسی طرح کا برقعہ اوڑھا کریں جو افغان بہنیں اوڑھتی ہیں۔ مصر اور ترکی کی مسلمان خواتین اپنے رواج کے مطابق حجاب اختیار کریں تو وہ بھی شریعت کے احکام کی تعمیل ہوگی۔
جس چیز کی پابندی لازمی ہے، وہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوص اور قطعی احکام ہیں جن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان یعنی قرآن و سنت کے منصوص اور قطعی احکام اور مقامی رواج کے درمیان فقہاے اسلام کے اجتہادات کا درجہ ہے۔ وہ اگر متفق علیہ ہیں یعنی ان پر اجماع یا نیم اجماع ہوچکا ہے تو ان کی پابندی بھی کی جانی چاہیے، لیکن اگر وہ انفرادی اجتہادات ہیں جن کے بارے میں اختلاف رائے کبار فقہا اور صحابہؓ کے زمانے سے ہمیشہ سے چلا آرہا ہو، وہاں شدت سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اس دور کے بعض علما اگر اس سے اختلاف کرتے ہوں، دلائل کی بنیاد پر کوئی اور رائے رکھتے ہوں اور کچھ لوگ اس رائے پر عمل کرنا چاہیں تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ ان کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ دلائل کی بنیاد پر جو رائے اختیار کرنا چاہیں، وہ اختیار کریں۔ اگر دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے فقہا کا اجتہاد قابل احترام ہے تو چودھویں اور پندرہویں صدی کے مخلص، ذی علم اور صاحب تقویٰ فقہا کا اجتہاد بھی قابل احترام ہے۔ جو حضرات سابقہ مجتہدین کے اجتہاد پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ اس پر عملدرآمد کے پابند اور مکلف ہیں جو حضرات چودھویں اور پندرھویں صدی کے فقہا کے اجتہادات پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ اس پر عملدرآمد کے پابند اور مکلف ہیں۔ دونوں کو مقامی رواج کسی پر مسلط کرنے کا حق حاصل نہیں۔ دونوں کو شریعت کے منصوص احکام سے انحراف کی اجازت نہیں۔ ان حدود کے اندر حجاب سے متعلق جو طریقہ کار بھی عامۃ الناس اختیار کرنا چاہیں، وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔
حجاب دراصل ان راستوں کا سدباب کرنے کے لیے ہے جن کے نتیجے میں قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، بداخلاقی جنم لیتی ہے اور فحاشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ صرف فحاشی کا ماحول پیدا نہیں ہوتا بلکہ خاندانی ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے، تعلقات کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی یہ ایک عام مشاہدہ ہے جسے ہر شخص دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ پھر شریعت نے محض حجاب کے احکام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فسق و فجور کے تمام دوسرے اسباب کا بھی سدباب کیا، برائی اور بے حیائی کے تمام راستے روکے۔ شریعت نے سخت سزائیں رکھیں، سخت سزائیں ان جرائم کی رکھیں ہیں جو انتہائی نوعیت کے جرائم ہیں۔ جس طرح سزائیں انتہائی نوعیت کی ہیں، اسی طرح جرائم بھی انتہائی نوعیت کے ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ حد قذف ہو ، حد رجم ہو، حد جلد یعنی تازیانہ ہو، ان سب کا مقصد منفی طور پر ان راستوں کو بند کردینا ہے جو تحفظ نسل اور تحفظ نسب کو مجروح کرتے ہیں۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۵۱-۲۵۳)
اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور موجودہ بے حیا تہذیب
حیا وحجاب پر مبنی اسلام کی تعلیمات پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’غیروں کے لیے ہدایات ہیں کہ خواتین کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کو دیکھ کر نظریں نیچی کرلو۔ انسانوں کا مزاج یہ رہا ہے کہ جس کا انتہائی احترام پیش نظر ہوتا ہے، اس کے سامنے نظریں نیچی ہوجاتی ہیں۔ جب خواتین کے روبرو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بحیثیت مجموعی صنف خواتین کو احترام کا وہ مقام حاصل ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اجنبی مرد ان کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچی کرلے۔ خواتین کو حکم ہے کہ اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں۔ خواتین کی زینت کوئی بازار کی جنس نہیں ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے سجا کر رکھ دی جائے۔ وہ انتہائی قابل احترام اور مقدس نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کو صرف اللہ کی حدود کے اندر استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کی بیان کردہ حدود کے اندر خواتین اس کا اظہار کرسکتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں احکام دیے گئے ہیں۔ یہ احکام کوئی نئے یا ایسے نہیں ہیں جو پہلی مرتبہ قرآن نے دیے ہیں، بلکہ ہر متمدن اور مہذب قوم نے کوئی نہ کوئی تصور ان احکام کا یعنی پردے اور حجاب کا دیا ہے۔ عریانی اور برہنگی کبھی بھی انسانیت کا شعار نہیں رہی۔ موجودہ لامذہب اور لا اخلاق معاشرے سے پہلے برہنگی اور عریانی سلیم الطبع انسانوں میں ناپسندیدہ اور مکروہ چیز سمجھی جاتی تھی۔عریانی اور برہنگی ہر قوم میں ایک بے حیائی اور فحاشی سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی سلیم الطبع انسان اسے بے حیائی اور فحاشی ہی سمجھتے ہیں۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۵۵)
امامت وحکومت کے مقاصد
امامت و حکومت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:
’’سیدنا علی ابن ابی طالب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ امامت اور امارت مسلمانوں کے اجتماعی وجود کے لیے ناگزیر ہے۔ امام یا امیر نیک ہو یا بدکار، اس کا وجود بہرحال ناگزیر ہے۔ امیرالمؤمنین سے سوال کیاگیا کہ نیکوکار قائد تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بدکار قائد کا وجود کیوں ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا: قائد اور امام اگر بدکار بھی ہوگا تو کم از کم حدود قائم ہوتی رہیں گی، راستے پُرامن رہیں گے، جہاد کا تقاضا پورا کیاجاسکے گا۔ عامۃ الناس کے مادی حقوق اور مالی واجبات ادا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اگر سربراہ ریاست نیکی اور تقویٰ کے اس معیار پر نہیں ہے جو شریعت کو مطلوب ہے تو بھی اس کا وجود بہرحال ناگزیر ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب جس بدکار اور غلط کار حکمران کا وجود تصور فرمارہے تھے، اس کے بارے میں بھی ان کو یہ یقین ضرور تھا کہ ایسے بدکار حکمران بھی، ایسے فاسق وفاجر حکمران بھی حدود قائم کریں گے، راستوں کو پُرامن بنائیں گے، دشمن کے خلاف جہاد کریں گے اور عامۃ الناس کے حقوق کی پاسداری کریں گے۔ آج ان میں سے شاید ہی کوئی ذمہ داری دنیاے اسلام میں ریاست کی طرف سے ادا کی جارہی ہو۔ حدود کتنی قائم کی جارہی ہیں؟ راستے کہاں کہاں اور کتنے پُرامن ہیں؟ دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کون کررہا ہے؟ عامۃ الناس کے مالی واجبات کون ادا کررہا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام کہاں کہاں قائم ہے؟ کتنے مستحقین کو زکوٰۃ مل رہی ہے؟ یہ واقعی ایک سوالیہ نشان ہے جو پوری امت کے جواب کا منتظر ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۸۶)
امامت کا قیام فرض کفایہ ہے
اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:
’’امامت کا قیام فرض کفایہ ہے اور واجب ہے۔ اس کے لیے فقہاے اسلام نے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ ایک بڑی دلیل جو ہر جگہ دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔یہ فقہ اسلامی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز پر کسی واجب کے ادا کیے جانے کا دارومدار ہو، وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ چونکہ اسلامی قوانین کا نفاذ واجب ہے، ایک دینی فریضہ ہے اور یہ فریضہ ریاست کے وجود کے بغیر انجام نہیں دیاجاسکتا، اس لیے ریاست کا وجود بھی ضروری ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۸۷)
وہ فقہاے اسلام کے حوالے سے اپنی بات کو مزید مدلل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’ماوردی، ابویعلی اور دوسرے بہت سے اہل علم نے بار بار یہ لکھا ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے ریاست کا وجود ناگزیر ہے۔ یہ بات آج کے سیکولر معاشرے کو عجیب معلوم ہوگی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میں ریاست اور دین، مذہب اور سلطنت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماوردی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب دین کمزور پڑتا ہے تو حکومت بھی کمزور ہوجاتی ہے اور جب دین کی پشت پناہ حکومت ختم ہوتی ہے تو دین بھی کمزور پڑجاتا ہے۔ اس کے نشانات مٹنے لگتے ہیں، اس کے احکام میں لوگ ردوبدل شروع کردیتے ہیں اور ہر شخص نئی نئی بدعتیں نکالنے لگتا ہے۔ یوں ہوتے ہوتے دین کے سارے آثار مٹنے لگتے ہیں۔ اگر حکومت دین کا دفاع نہ کرے اور دین کا تحفظ نہ کرے تو لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس حکومت کو عامۃ الناس کی طرف سے مدد اور اطاعت نہیں ملے گی۔ وہ حکومت نہ قائم ہوسکے گی جو دین کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے، نہ اپنے معاملات کو صاف انداز میں چلاسکے گی۔ اس کے نتیجے میں استبداد قائم ہوگا۔ معاشرے میں انتشار پھیلے گا اور طرح طرح کی تباہیاں پیدا ہوں گی۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۸۷-۲۸۸)
ریاست و دین کے ناگزیر تعلق کو وہ تاریخی ثبوت سے واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’عبداللہ ابن المعتز ایک مشہور ادیب، شاعر اور نقاد تھا۔ ایک روز کے لیے خلیفہ بھی رہا۔ اس کو ایک ہی دن بعد معزول کردیاگیا تھا۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حکومت دین ہی کی بدولت قائم رہ سکتی ہے اور دین ریاست اور حکومت ہی کی وجہ سے تقویت پاسکتا ہے۔ اسلامی تصور یہی ہے کہ دین اور ریاست دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہوں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے ماہر اجتماعیات ابن خلدون نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر کسی ریاست کو دینی دعوت کی مدد حاصل ہو اور ریاست کو دین کی پشت پناہی میسر ہوتو اس کی عصبیت مضبوط رہتی ہے، اس کی تائید کرنے والے یکجا رہتے ہیں اور ان میں آپس میں جو حسد اور مقابلے بازی ہے، وہ ختم ہوجاتی ہے اور سب مل کر مشترکہ دینی مقاصد اور مشترکہ اجتماعی اہداف کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب بھی دین کی قوت کمزور پڑے گی تو لسانی، قبائلی، علاقائی اور مقامی عصبیتیں جنم لیں گی اور اصل مقصد سے توجہ ہٹ جائے گی، لیکن اگر دینی دعوت مضبوط ہوتو پھر مقامی عصبیتیں سر نہیں اٹھاتیں اور سب کی توجہ اصل مقصد کی طرف لگ جاتی ہے۔ ابن خلدون نے تاریخ کے واقعات سے قادسیہ اور یرموک کی کامیابیوں سے، موحدین کے پورے دور کی تاریخ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں وہ ریاستیں کامیاب رہی ہیں جن کے دور میں دینی دعوت مضبوط تھی، جو دین کی پابند تھیں اور دین ہی کی مدد سے ان کو قوت مل رہی تھی۔
اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائز لیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیشتر بڑی بڑی مملکتیں مذہب ہی کی بنیاد پر، یعنی اسلام کی بنیاد پر ہی قائم ہوئیں۔ یہ بات ابن خلدون نے تو کہی ہے، لیکن تاریخ کے مشاہدے سے بھی یہی انداز ہ ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان مغربی نظام جمہوریت کا انکار کرکے ہی قائم ہوسکا، مغربی تصور قومیت کو مسترد کرکے قائم ہوا۔ تحریک پاکستان کے دوران سب سے بڑا حوالہ امت مسلمہ، اسلامی شریعت اور مسلم برادری کا حوالہ تھا۔ افغانستان کی ریاست جب قائم ہوئی، آج نہیں، جب احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں قائم ہوئی تو احمد شاہ ابدالی نے آخر کیا کہہ کر افغانیوں کو اپیل کیاتھا؟ اس نے افغانیوں کو اسلام کے نام پر جمع ہونے کو کہا تھا۔ سعودی عرب کی حکومت تو خالص اسلامی دعوت ہی کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ موجودہ ایران، موجودہ لیبیا، موجودہ مراکش، یہ سب اپنے اپنے اوقات میں خالص دینی دعوت کی بنیاد پر بننے والی ریاستیں ہیں۔ سلطنت بنی عباس اور سلطنت عثمانیہ کا آعاز بھی دینی دعوت سے ہوا۔ مغلوں کے دور کی اسلامی ریاستیں، ایران کی صفوی ریاست خالص مذہبی دعوت کی بنیاد پر قائم ہیں۔ سلطنت مغلیہ کیسے قائم ہوئی؟ بابر کو یہاں کے مسلمان حکمرانوں نے ، علما نے، مسلمان قائدین نے خطوط لکھے تھے۔ ملت مسلمہ کے تحفظ کے لیے اس کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔
اسلامی تاریخ پر ہم جتنا بھی غور کریں اور بڑی بڑی مسلم ریاستوں کے آغاز کا جائزہ لیں تو واضح ہوتا ہے کہ ان میں بیشتر کا آغاز دینی محرکات کی بنیاد پر ہوا ہے اور جب تک وہ دینی محرک قوی رہا، ریاست قوی رہی۔ جب دینی محرک کمزور ہوگیا، ریاست کی بنیادوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۸۸-۲۸۹)
ریاست کے دینی تصور پر امت کے تمام فرقوں کا اتفاق
محترم غازی صاحبؒ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’صدر اسلام کی تاریخ سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ جوش و خروش سے جس معاملے پر بحث ہوئی، جس کی بنیاد پر مختلف مسالک وجود میں آئے، کلامی فرقے بنے، مختلف مواقع پر جنگیں بھی ہوئیں، وہ یہی امامت اور ریاست کا مسئلہ تھا۔ امامت اور ریاست کے دینی بنیادوں پر قائم ہونے کو ہر مسلمان مکتب فکر کے نزدیک مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ اس اصول کے سب قائل ہیں۔ وہ شیعہ ہوں، اہل سنت ہوں، خوارج ہوں، زیدی ہوں، یہ سب کے سب ریاست کے دینی تصور اور مذہبی بنیادوں کو مانتے تھے اور نظری اور کلامی اعتبار سے آج بھی مانتے ہیں۔ ان سب کلامی مدارس کے درمیان جو چیز قدر مشترک ہے، وہ ریاست اور مملکت کا دینی بنیادوں پر قائم ہونا ہے۔ علامہ شہرستانی مشہور متکلمین اسلام میں سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا اور طویل ترین اختلاف جس معاملے پر رہا ہے، وہ ریاست اور امامت کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کسی مذہبی معاملے پر اتنی بار تلوار نہیں اٹھائی گئی ہے جتنی بار امامت اور ریاست کے مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فکر اسلامی میں ریاست کا وجود کس حد تک ضروری اور کتنا ناگزیر سمجھا گیا۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۸۹-۲۹۰)
ان کی گفتگو اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں:
’’جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات اسلامی عقائد کا حصہ بن گئی تھی اور متکلمین اسلام اس کو عقیدے کے طور پر بیان کرتے تھے۔ عقائد کی مشہور کتاب جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے یعنی’’ شرح عقائد نسفی‘‘، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسے امام یعنی ریاست کا وجود ناگزیر ہے جو شریعت کے احکام نافذ کرے، حدود کو قائم کرے، سرحدوں کا دفاع کرے، فوجوں کو تیار رکھے، زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کا نظام قائم کرے، چوروں و ڈاکوؤں اور فساد پھیلانے والوں پر کنٹرول کرے، جمعوں اور عیدوں کی نمازوں کا انتظام کرے، عامۃ الناس کے درمیان اگر اختلافات یا تنازعات ہوں تو ان کا فیصلہ کرے، حق اور انصاف کی بنیاد پر گواہیاں قبول کرنے کا نظام قائم کرے، چھوٹے بچوں اور بچیوں کی سرپرستی کرے، جن کا کوئی سرپرست نہ ہو ان کے حقوق کی نگہداشت کرے، جو نوجوان بے سہارا ہیں ان کی شادیوں کا اور ازدواجی زندگی کا انتظام کرے، غنیمت اگر کہیں سے حاصل ہوئی ہے، اس کی تقسیم کا انتظام کرے اور وہ تمام کام انجام دے جو افراد انجام نہیں دے سکتے لیکن جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست کے وہ بنیادی فرائض بھی ہیں جو فقہاے اسلام نے بیان کیے ہیں۔ ان فرائض کے علاوہ دیگر فرائض بھی بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۸۹-۲۹۰)
تھیوکریسی کی لعنت سے پاک ایک دینی ریاست
محترم غازی صاحبؒ اسلامی ریاست کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’اسلامی ریاست ایک دینی ریاست ہے۔ اس مفہوم میں کہ وہ خالص دینی تعلیم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، دینی اہداف کی علمبردار ہے، دینی احکام پر عملدرآمد کی پابند ہے، ایک ایسے قانون کے نفاذ کی مکلف ہے جو دینی قواعد اور تعلیمات پر مبنی ہے۔ لیکن دینی ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ریاست مغربی تھیوکریسی کے مفاسد اور نقائص سے مکمل طور پر پاک ہے۔ یہاں نہ اہل مذہب کا کوئی پیدائشی طبقہ ہے، نہ کوئی پوپ ہے، نہ کوئی چرچ ہے، نہ اہل مذہب کو کوئی ایسے اختیارات حاصل ہیں جو عامۃ الناس کو حاصل نہیں ہیں۔ یہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان ہر وقت ایک ہاٹ لائن قائم ہے۔ بندہ جب چاہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے رجوع کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہاں گناہ بخشوانے کے لیے کسی پادری یا پروہت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ اور رسول کے بعد کسی بڑے سے بڑے آدمی کا قول و فعل حجت نہیں ہے۔ اس لیے تھیوکریسی کے جتنے مفاسد ہیں جن کی وجہ سے اہل مغرب تھیوکریسی کے نام سے ہروقت خائف رہتے ہیں، وہ مفاسد اسلامی ریاست میں موجود نہیں ہیں۔‘‘ (ایضاً)
اسلامی ریاست کی صفات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:
’’اسلامی ریاست ایک جمہوری ریاست ہے، لیکن جدید سیکولرڈیموکریسی کے جمہوری مفاسد سے پاک ہے۔ آج مغربی جمہوریت نے خاصے مفاسد پیدا کردیے ہیں، اس لیے کہ مغربی جمہوریت نے کثرت اور قلت تعداد کو حق و باطل کا معیار قرار دے دیا ہے۔ جس طرف اکاون فیصد ہیں، وہ حق ہے۔ جس طرف انچاس فیصد ہیں، وہ باطل ہے۔ اسلام اس کثرت و قلت کے اصول کو قبول نہیں کرتا۔ حق حق ہے، چاہے ساری انسانیت اس کی مخالف ہو۔ باطل باطل ہے، چاہے ساری دنیا اس کی حامی ہو۔ لوگوں کی تائید اور مخالفت سے حق کے حق ہونے میں اور باطل کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق وہ ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ باطل وہ ہے جس کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے۔ اس لیے حق و باطل کا معیار وہی ہے جو شریعت میں ہے۔ ریاست کا بنیادی قانون وہی ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ ریاست کے مقاصد وہی ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں۔ ان حدود کے اندر کہ ریاست شریعت کی بالادستی کی علمبردار ہو، شریعت ملک کا بالاتر قانون ہو، ان حدود کے اندر عامۃ الناس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے سربراہوں کا انتخاب کریں، اجتہادی معاملات میں فیصلے کریں۔ اجتہادی آرا اگر ایک سے زائد ہوں تو ان میں سے جس رائے کو عامۃ الناس اختیار کرلیں، وہ رائے اسلامی قانون ہے۔ جن معاملات میں شریعت نے امت کو آزاد چھوڑا ہے اور وہ زندگی کے بیشتر معاملات سے عبارت ہے، وہاں امت اپنے اجتماعی فیصلے سے جس رائے کو اختیار کرنا چاہے کرسکتی ہے۔ اس لیے یہاں جمہوریت کی حقیقی روح موجود ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار کہا تھا کہ ’’مسلمانوں سے زیادہ جمہوریت پسند کون ہوسکتا ہے جو مذہب میں بھی جمہوریت پسند ہیں، جن کا مذہب بھی خالص جمہوری انداز سے کام کرتا ہے‘‘۔ نماز جیسی عبادت میں امامت کرنے کے لیے جس کو عامۃ الناس پسند کریں، وہی امامت کرسکتا ہے۔جس کو عامۃ الناس، ناپسند کریں اور وہ امامت کرنے لگے تو اس کو ناپسند کیاگیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے: لعن اللّٰہ امام قوم وہم لہ کارہون۔اللہ تعالیٰ اس امام پر لعنت بھیجتا ہے جو زبردستی لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ اس لیے جمہوریت کی روح تو اسلام کی رگ رگ میں موجود ہے۔ لیکن یہ جمہوریت جدید لادینی ڈیموکریسی کے مفاسد سے مکمل طور پر پاک ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۹۴۔۲۹۵)
حکمرانی کے جواز کے بنیادی ترین شرائط
ڈاکٹر محمود غازیؒ امت کے متفق علیہ فکر کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جائز حکمران کی کم از کم شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’اگر کسی شخص نے قوت حاصل کرکے اپنے گرد فوج اکٹھی کرکے ریاست پر قبضہ کرلیا اور اپنے کو حکمران قرار دے دیا، اب اگر وہ شریعت کے احکام نافذ کررہا ہے، دین کا تحفظ کررہا ہے، دنیوی معاملات کی تدبیر اور نظم و نسق ٹھیک چلا رہا ہے تو اسے قبول کرلینا چاہیے۔حاکم متغلب یعنی زبردستی قبضہ کرلینے والا حکمران جائز حکمران تسلیم کیاجائے گا، اگر وہ شریعت کی بالا دستی کو مانتا ہو، شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہو اور شریعت کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ بات تمام فقہاے اسلام نے لکھی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی حاکم متغلب یا زبردستی مسلط ہونے والا حکمران شریعت کے احکام نافذ کرتا ہو، حدود قائم کرتا ہو، ملک کا دفاع کرتا ہو، لوگوں کی عزت و آبرو کا محافظ ہو، دشمنان اسلام سے جہاد کے لیے فوجیں تیار رکھتا ہو، زکوٰۃ و صدقات کا نظام قائم کرتا ہو، عدالتیں آزادی سے کام کررہی ہوں، جمعہ، عیدین اور نمازوں کا نظام قائم ہو، مظلوم کو انصاف مل رہا ہو، ظالم کو ظلم سے روکا جارہا ہو، عدالتیں اور دوسرے ادارے کام کررہے ہوں، دنیا کے مختلف گوشوں میں داعی اور قاری بھیجے جارہے ہوں تو پھر وہ ریاست جائز ریاست مانی جائے گی۔ یہ تمام فرائض جو میں نے ابھی بیان کیے، وہ ہیں جو علامہ شہرستانی نے اپنی مشہور کتاب ’’نہایۃ الاقدام فی علم الکلام‘‘ میں بیان کیے ہیں۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۲۹۸-۲۹۹)
ریاست کا اولین فریضہ۔۔۔سیکولرازم کی جڑپرتیشہ
ریاست کے پہلے فریضہ پر بات کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:
’’یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نماز جو عبادات کا سب سے بنیادی عنوان ہے، سب سے اولین اور بنیادی عبادت ہے، اس کو ریاست کا سب سے پہلا فریضہ قرار دیاگیا ہے۔ یہاں لامذہبیت اور سیکولرزم کی جڑ کٹ جاتی ہے، اس لیے کہ حکومت کے اہم ترین فرائض میں سے اقامت صلوٰۃ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مرتبہ اپنے تمام گورنروں کو لکھا تھا کہ آپ حضرات کے فرائض میں سے سب سے اہم ترین فریضہ میرے نزدیک اقامت صلوٰۃ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں فوج کے سربراہ ہی نماز کے امام ہوتے تھے۔ جو امام صلوٰۃ ہوتا تھا، وہ امام جیش بھی ہوتا تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب جب خلافت کے لیے ہونے لگا تو صحابہ کرامؓ نے متفقہ طور پر ان کی امامت صلوٰۃ کو امامت ریاست کی بنیاد قرار دیا اور کہا جس شخص کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب سے بڑی عبادت کے لیے چنا کہ وہ ہماری امامت کرے، ہم ان کو دنیوی معاملات میں بھی اپنی امامت کے لیے منتخب کریں گے۔ اس لیے اگر سربراہ ریاست امامت صلوٰۃ کا اہل ہوگا تو ظاہر ہے امام صلوٰۃ کے لیے جولازمی خصوصیات ہونی چاہییں، وہ اس میں پائی جانی چاہییں۔ یہ وہ کم سے کم اہلیت ہے جو اسلامی ریاست کے سربراہ میں پائی جانی چاہیے۔ کم از کم نماز پڑھنا جانتا ہو، اتنا قرآن جانتا ہو کہ نماز ادا کرسکے، نماز کے احکام سے واقف ہو۔ جس نے سرے سے کبھی زندگی میں نماز نہ پڑھی ہو، جو سرے سے نماز پڑھنا ہی نہ جانتا ہو، وہ اسلامی ریاست کا سربراہ ہوجائے، یہ بات اسلامی معیار اخلاق اور اسلامی سیاست کی رو سے ناقابل تصور ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۳۰۰)
نظریہ پاکستان: لادینی مغربی نظریات کا انکار
اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’اسی طرح تحریک پاکستان کی شکل میں جو ایک اسلامی ریاست کے قیام کی ایک اجتماعی کوشش تھی، یہی جذبہ کار فرما تھا۔ تحریک پاکستان دراصل ان مغربی تصورات کے انکار پر مبنی تھی جو دور جدید میں رائج تھے اور جدیدلادینی اور سیاسی تصورات پر مبنی تھے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی اساس اور اٹھان دو قومی نظریے پر ہے۔ یہ نظریہ قومیت اور نیشنل ازم کے جدید مغربی نظریے کے انکار پر مبنی ہے۔ جدید مغربی تصورات کے انکار و استرداد پر مبنی ہے۔ نظریہ پاکستان اور جدید لادینی نظریات اور تصورات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔پاکستان کی پریشانی اور مشکلات کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ قائدین تحریک پاکستان کے بعد جو لوگ پاکستان پر مسلط ہوئے، وہ تحریک پاکستان کی روح سے قطعاً ناآشنا رہے ہیں۔ اسی طبقہ نے جدید لادینی مغربی تصورات کو پاکستان میں جاری کرنا چاہا۔ اہل پاکستان کی نفسیات اور مزاج نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کشمکش پیدا ہوئی۔ ‘‘(ایضاً صفحہ ۳۰۹)
مسلمانوں کے سیاسی زوال اور معاشرتی انحطاط میں کرنے کا اولین کام
محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کردار اور اخلاق کی بنیادی ترین اہمیت کا واضح شعوررکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:
’’جس زمانے میں صوفیانہ مضامین کو نظم کرنے والے شعرا سامنے آئے، یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کا سیاسی زوال اور معاشرتی انحطاط بہت نچلی حدود کو چھورہا تھا۔ بغداد کا زوال ہوچکا تھا۔ تاتاریوں نے پوری دنیاے اسلام کو برباد کردیاتھا۔ بڑے بڑے جید علماء کرام شہید ہوچکے تھے اور مسلمانوں کا کوئی سیاسی مقام یا وقار دنیا میں نہیں رہا تھا اور ہر طرف مایوسی پھیل رہی تھی۔ اس مایوسی کے عالم میں بعض صوفیاے کرام نے مسلمانوں کو امید کا پیغام دینا چاہا جن میں سب سے بڑا نام مولانا جلال الدین رومیؒ کا ہے۔ انہوں نے اتنے زوروشور سے رجائیت کا یہ نغمہ بلند کیا اور لوگوں کو بلند آواز اور آہنگ یہ بات یاددلائی کہ اسلام کا مقصد کسی مادی مفاد کا حصول نہیں ہے یا ریاست اور سلطنت کا قیام اصلی مقصود نہیں ہے۔ یہ ایک ثانوی چیز ہے۔ اصل چیز کردار اور شخصیت کی تشکیل و تعمیر ہے، روحانیت کی تشکیل و تعمیر ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۳۵۰)
اہل مغرب اور اہل اسلام کی سوچ کا بنیادی فرق
اپنے خوبصورت اور سلیس انداز بیان کے ذریعے اہل مغرب اور اہل اسلام کی سوچ کا فرق یوں واضح فرماتے ہیں:
’’اہل مغرب نے آج سے طویل عرصہ قبل (تقریباً دو ہزار سال پہلے) یہ طے کرلیاتھا کہ عقل اور وحی میں کوئی توافق نہیں ہے اور ان دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ انہوں نے ایک جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا، معلوم نہیں وہ واقعتاً ان کا جملہ تھا یا نہیں۔ اگر انہوں نے ارشاد فرمایا ہوگا تو یقیناًکسی اور مفہوم میں ہوگا۔ بظاہر تو ان کا ارشاد معلوم نہیں ہوتا کہ ’’جو قیصر کا ہے، وہ قیصر کو دے دو۔ جو اللہ کا ہے، وہ اللہ کو دے دو۔‘‘ اس کی بنیاد پر مسیحی دنیا نے مذہب اور ریاست دونوں کا دائرہ کار الگ طے کردیا۔
آج اہل مغرب دنیا میں جس سے بھی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، وہ دین و دنیا کی اسی تفریق کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں کہ عقل اور وحی میں کوئی توافق نہیں ہے۔ ان کا اصرار اور مطالبہ، بلکہ شدید دباؤ ہے کہ ان دونوں میں تفریق کے اصول کو تسلیم کروگے تو بات آگے بڑھے گی۔ جو قوم یا افراد اس تفریق کے قائل نہیں ہیں، ان سے مغرب کوئی آبرومندانہ معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام کے نظام میں عقل اور وحی ایک دوسرے کے حریف نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، یعنی انسانی علم یا سائنس اور مذہبی علم اور ہدایت یہ ایک دوسرے کے مؤید اور تکمیل کنندہ ہیں، ایک دوسرے کی نفی کرنے والے نہیں ہیں۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۰۶)
روحانی اقدار اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ہم آہنگی کیسے ہو؟
محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
’’اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عقل اور نقل کا یہ مکمل توازن اور ہم آہنگی شریعت کے بنیادی مزاج کا حصہ ہے تو پھر جدید مادی آسائشیں اور جدید مادی کامیابیاں دینی اور اخلاقی اقدار سے ہم آہنگ کیسے کی جائیں؟ یہ بات متعدد مغربی مفکرین نے تسلیم کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اخلاقی اور روحانی اقدار سے ہم آہنگ کرنے میں اگر کوئی قوم یا تہذیب تاریخ کے اس طویل عرصہ میں کامیاب ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں کو جو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اخلاقیات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تقاضوں میں تعلق اور نسبت کیا ہے؟ اس کا تعین کیسے اور کن اصولوں کے تحت کیاجائے؟ اگر یہ کہیں کہیں متعارض ہیں تو وہ کون کون سے مسائل اور معاملات ہیں؟ اگر یہ باہم متوافق ہیں تو کہاں کہاں ہیں؟ باہم غیر جانبدار ہیں تو کہاں کہاں ہیں؟ اور ان تینوں صورتوں کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس رویہ کے تعین میں جو بنیادی حقیقت مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے ،جو ماضی قریب میں بعض مفکرین اور اہل دانش کی نظروں سے کئی بار اوجھل ہوگئی، وہ شریعت کا دوام اور تسلسل ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۰۷)
اسلامی شریعت۔۔۔ثبات اور تغیرکا حسین نمونہ
شریعت کے دوام اور تسلسل کے نکتے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’مغرب نے اپنے خاص مزاج اور دوسرے مختلف اسباب کی بنا پر تغیر کو ایک مثبت اور قابل فخر نعرے کی شکل دے دی ہے۔ آج کے مغرب میں ہر نئی چیز قابل قبول ہے اور ہر قدیم چیز ناقابل قبول ہے۔ مغرب کا یہ مزاج پچھلے دو تین سو سال میں بنادیاگیا ہے اور اس مزاج کو بنانے میں وہ تاجر ، صنعتکار اور کارخانے دار بھی شامل ہیں جو اپنے خالص مادی مفاد کی خاطر ہر نئی چیز کے لیے مارکیٹ اور بازار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر نئی چیز کے لیے بازار جب پیدا ہوگا جب ہر قدیم چیز کو ناپسندیدہ ٹھہرایاجائے گا۔یہ سلسلہ گزشتہ دو، ڈھائی سو برس سے جاری ہے۔ اس مسلسل یک طرفہ مہم کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر قدیم چیز ناپسندیدہ اور منفی بن گئی ہے اور ہر جدید چیز پسندیدہ اور مثبت سمجھی جانے لگی ہے۔ یہ مزاج اور رویہ مغربی تہذیب کے تاجرانہ مزاج نے پیدا کردیا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں کوئی چیز نہ محض اس لیے اچھی یا بری ہے کہ وہ قدیم ہے اور نہ محض اس لیے اچھی یا بری ہے کہ وہ جدید ہے۔ نہ محض اس لیے پسندیدہ اور قابل قبول ہے کہ قدیم ہے، نہ اس لیے ناقابل قبول ہے کہ جدید ہے۔ کسی چیز کی قدامت اور جدت اسلام میں پسندیدگی کا معیار نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام قصہ جدید و قدیم کو دلیل کم نظری سمجھتا ہے۔ جو چیز دراصل اسلام میں بقا اور تسلسل کی ضامن ہے اور جس بقا اور تسلسل کا مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے، وہ دائمی و ازلی دینی اقدار ہیں جو قرآن پاک و سنت ثابتہ میں بیان ہوئی ہیں اور ان ازلی حقائق کے ساتھ ساتھ دین وشریعت کی وہ متفقہ تعبیرات اور تشریحات بھی تسلسل کی ضامن ہیں جن پر مسلمانوں کا روزاول سے اتفاق رہا ہے۔ یہ جو متفقہ تعبیرات ہیں، ان کی حیثیت اس پشتے کی ہے جس سے کسی دیوار کو سہارا دیاجاتا ہے۔ جب بنیاد بنائی جاتی ہے تو بنیاد کی حفاظت کے لیے بھی ایک پشتہ ہوتا ہے۔ یہ متفق علیہ تعبیرات اس پشتے کی حیثیت رکھتی ہیں جو اس بنیاد کی حفاظت کے لیے فراہم کیاگیا ہے۔ اس لیے اس بنیاد کے ساتھ ساتھ اس پشتہ کے بارے میں بھی کوئی مداہنت نہیں ہوسکتی، اس لیے کہ پشتہ کمزور ہوگا تو بنیاد بھی کمزور ہوگی۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۰۸)
’’اسی لیے یہ دینی حقائق جو قرآن پاک و سنت ثابتہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن کو مسلمانوں کی متفقہ تعبیرات اور اجتماعی فہم کے پشتے نے مزید محفوظ و مضبوط بنایاہے، ان کی حیثیت روحانی اور اخلاقی دنیا میں اس خیر اور ابقی کی ہے جس کے نمائندے بڑے بڑے انبیاے کرام علیہم السلام رہے ہیں اور اس دوام خیر اور تسلسل حق کو یقینی بنانے میں ان بنیادوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس خیر و ابقیٰ کی حفاظت کے بعد ہر تغیر و جدت قابل قبول ہے۔ اس بنیاد کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ ساتھ اس پشتے کے چاروں طرف جتنی جدتیں اور تغیرات انسان لا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۰۹)
معاشی خود مختاری کی اہمیت
معاشی خودمختاری کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
’’امت مسلمہ کی دیرپا سیاسی آزادی اور بامعنی عسکری اور دفاعی قوت کے حصول کے لیے معاشی خودمختاری درکار ہے۔ مسلمانوں کے لیے معاشی آزادی کے حصول کو فقہاے اسلام نے فرض کفایہ قرار دیاہے۔ یہ بات میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، امام غزالی اور کئی دوسرے فقہاے کرام کے حوالے سے پہلے بھی بیان کرچکا ہوں۔ جب تک مسلمان معاشی طور پر آزادتھے، ان کی تہذیب غالب تہذیب تھی اور مقصدیت کی بنیاد پر قائم تھی۔ جب معاشی آزادی ختم ہوگئی تو ان کی سیاسی طاقت بھی ختم ہوگئی اور ان کی تہذیب ایک غلامانہ تہذیب میں بدل گئی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ’’از غلامی دل بہ میرد در بدن‘‘، یعنی غلامی کی حالت میں دل اندر سے مرجاتا ہے۔ ’’از غلامی روح گردد بارتن‘‘، غلامی کی حالت میں روح بوجھ بن جاتی ہے۔ ’’از غلامی شیر غاب افگندہ ناب‘‘، جنگل کے شیر غلامی کی حالت میں ایسے ہوجاتے ہیں جیسے دانت گرے ہوئے بوڑھے ہوتے ہیں۔ ’’از غلامی مرد حق زنار بند‘‘، غلامی میں مردان حق بھی زنار پوش ہوجاتے ہیں۔
آج دیکھ لیں کہ ہر جگہ مردان حق زنار بند نظر آتے ہیں۔ انگریزوں کی دوسو سالہ غلامی نے ہمتیں اتنی پست کردی ہیں کہ اب ہندوؤں کی تہذیبی غلامی کی نوبت آنے لگی ہے۔ جس قوم کے آباؤ اجداد نے ایک ہزار سال ہندوستان پر حکومت کی اور یہاں کی غالب ترین اکثریت کے علی الرغم شریعت اور اسلامی تہذیب کو جنوبی ایشیا کی بالادست تہذیبی قوت بنایا، ان کے ہاں آج کیا ہورہا ہے؟ شادی کی کسی تقریب میں جائیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ ہندوؤں کی شادی معلوم ہوتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے بچپن میں ہندوانہ رواج کی وجہ سے ناجائز سمجھی جاتی تھیں، وہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمانوں کے گھروں میں پھیل رہی ہیں۔ بے غیرت مسلمانوں نے سونیا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ ہندوستان کو اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، ہندوستان کے ٹی وی اور میڈیا نے پاکستان کی ثقافتی آزادی کو ختم کردیا ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۱۳۔۵۱۴)
علمائے سوء، دین کے ڈاکو
ڈاکٹر غازیؒ صاحب غلامانہ ذہنیت کے اسباب کا کھوج لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ذہنی غلامی کیوں پیدا ہوئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے احادیث میں جو کچھ آیا ہے اور اکابر اسلام نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو طبقوں کی گمراہی، کمزوری اور نالائقی سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ اپنے زمانے میں امیرالمؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے:
وھل افسد الدین الا الملوک
واحبارسوء و رہبانہا
دین کے معاملات کو دو چیزوں نے خراب کیا، ایک نالائق حکمرانوں نے، دوسرا علماء سو (یعنی بدکردار اور دنیا پرست علما) نے۔ جب یہ دو طبقے مسلمانوں میں خراب ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ خراب ہوجاتا ہے۔ جب علما کم فہم ہوں اور حکمران بدعمل ہوں تو مسلمان امت خرابی کا شکار ہوجاتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے کہا ہے کہ: علماء سوء لصوص دین اند (علماء سوء دین کے لیے ڈاکو ہیں۔) یہ مجدد الف ثانی کے الفا ظ ہیں، کسی عام اور دین سے بے بہرہ آدمی کے الفاظ نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء سوء کی صحبت سے ایسے بچو جیسے زہریلے سانپ کے قریب جانے سے بچتے ہو۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۱۴)
مغرب کا ایجنڈا
مغرب کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر محمود غازیؒ کو اس کا بڑا واضح شعور حاصل تھا۔لکھتے ہیں:
’’دنیائے اسلام میں بہت سے لوگ اب تک یہ سمجھتے تھے کہ مغرب کا ایجنڈامحض معاشی، سیاسی اور کسی حد تک ثقافتی ہے، اس ایجنڈے کا مذہب اور تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب جو بیانات اہل مغرب کی طرف سے آرہے ہیں اور اسلامی قوتوں کو جس طرح سے نشانہ بنایاجارہا ہے اور ہر مسلمان کو جس طرح اصول پسند یا بنیاد پرست قرار دے کر مسلسل حملوں کا ہدف بنایا جا رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ان کا ہدف براہ راست دین اور مذہب ہے۔ ان کے ہاں جو تحریریں پچھلے دس پندرہ سال میں شائع ہوئی ہیں، اس میں واضح طور پر کہاگیا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو قرآن پاک کو حقیقی مفہوم میں اللہ کا کلام سمجھتا ہے اور ظاہری مفہوم میں اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ بنیاد پرست (fundamentalist) ہے، چاہے عملاً نافذ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ جو قرآن کو کتاب ہدایت اور زندگی کا دستورالعمل سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ بنیاد پرست ہے۔ اس تصور کی رو سے ہر باعمل مسلمان بنیاد پرست قرار پاتا ہے بلکہ ایک بے عمل مسلمان بھی اگر قرآن کو کتاب الہٰی مانتا ہے تو وہ بھی بنیاد پرست ہے۔ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے۔ بنیاد پرستوں کے خلاف جنگ کرنے کے عزائم اتنی کثرت سے دہرائے گئے ہیں کہ اب یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ ان کا اصل ہدف کیا ہے۔ اب یہ بالکل واضح اور عیاں ہو چکی ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۱۸-۵۱۹)
اہل مغرب کی منفی و مثبت خصوصیات
اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ فرماتے ہیں:
’’اہل مغرب کے ہاں فکری یک رنگی موجود ہے۔ پورا مغرب ایک خاص رخ پر چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو رویہ فرانس اور پیرس میں محسوس ہوتا ہے، وہی رویہ دوسرے مغربی ممالک میں محسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو بات امریکہ میں کہی جارہی ہے، وہی اٹلی میں بھی کہی جارہی ہے، وہی اسپین میں بھی کہی جارہی ہے۔ ان کے ہاں عزم و ارادہ پایاجاتا ہے اور پچھلے دو سو برس سے دنیائے اسلام کے بارے میں وہ اپنے عزائم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اس معاملہ میں ان کے حکمرانوں اور عامۃ الناس کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تعلیم کی سطح ان کے ہاں اتنی اونچی ہے اور ان کے اپنے مقاصد سے اتنی ہم آہنگ ہے کہ دنیائے اسلام کے ممالک میں اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ان کی معاشی خوشحالی کی بنیاد بڑی مضبوط اور دیرپا ہے۔ وہ خود کفیل ہیں، ان کے پاس بے پناہ عسکری قوت ہے، ان کے ہاں سائنسی تحقیق کے ہزاروں ادارے کائنات کے ذرہ ذرہ اور چپہ چپہ کا سراغ لگارہے ہیں اور تکریم آدم کا تصور ان کے ہاں ایک حقیقت ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۱۹)
اہل اسلام کے انتشار کا نقشہ
ساتھ ہی مسلمانوں کے انتشار کی نقشہ کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں:
’’اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ دنیائے اسلام کا کوئی واضح نصب العین اور کوئی متعین ہدف نہیں ہے۔ عامۃ الناس کے عزائم اور خواہشات میں جو ہرجگہ یکساں ہیں اور حکمرانوں کے عزائم اور خیالات میں کوئی توافق اور ہم آہنگی نہیں۔ عامۃ الناس کی خواہشات، آرزوئیں اور امیدیں انڈونیشیا سے مراکش تک ایک جیسی ہیں، لیکن حکومتوں کا ، سیاسی قیادتوں کا اور فکری اور سرکاری سیاسی اور اقتصادی راہنماؤں کا کوئی ہدف نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فکری الجھنیں عام ہیں۔ کوئی عزم و ارادہ کسی سطح پر موجود نہیں ہے۔ آپس میں بدترین اختلافات ہیں، تعلیم کی سطح بہت پست ہے، معاشی بنیادیں کمزور ہیں۔ دنیائے اسلام میں جو ممالک بہت خوشحال نظر آتے ہیں، ان کی خوشحالی کی بنیاد بھی کوئی مضبوط اور دیرپا نہیں ہے۔ بہت سی صورتوں میں یہ ظاہری خوشحالی ہے اور بعض بااثر مغربی طاقتوں کی مبنی برمصلحت سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ اس خوشحالی کا کنٹرول اور سوئچ مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ سوئچ آف کردیاجائے تو ساری معاشی چکاچوند آن واحد میں ختم ہوجائے گی۔ مسلم ممالک کا دوسروں پر انحصار ہے، اکثر مسلم ممالک عسکری اور سائنسی طور پر کمزور ہیں۔ بے توقیری آدم کے نمونے ہر مسلم ممالک میں کثرت سے نظر آتے ہیں۔ یہ فرق اس وقت ہمارے اور دنیائے مغرب کے درمیان قائم ہے۔ ان حالات میں کیا دنیائے اسلام اور دنیائے مغرب میں مقابلہ برابر کا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے۔‘‘(ایضاً صفحہ ۵۱۹۔۵۲۰)
مغرب کے دو تباہ کن تحفے
’’مزید برآں انہوں نے دو بڑے تباہ کن تحفے دنیائے اسلام کو دیے ہیں۔ پہلے ایک تحفہ دیا جس کے ذریعے دنیائے اسلام کو تباہ و برباد کردیاگیا۔ اب دوسرا تحفہ آرہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فی الوقت کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ پہلا تحفہ جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کہا تھا: "the most dreadful enemy of humanity" کہ میں جس کو اسلام کا سب سے تباہ کن دشمن سمجھتا ہوں، وہ ’’قومیت اور علاقائی نیشنل ازم کا نظریہ (territorial nationalism) ‘‘ہے۔ اسی علاقائی قومیت نے دنیائے اسلام کو چھوٹے چھوٹے ملکوں اور رجواڑوں میں تقسیم کرکے رکھ دیا۔ ........
نیشنل ازم نے جو حال مسلم ممالک کا کیا ہے، اس سے مسلمانوں کو ابھی تک سبق نہیں ملا۔ دوسو سال کے طویل اور تکلیف دہ تجربات بھی انہیں کوئی سبق نہیں سکھا سکے۔ اب جو مزید تحفہ دیاجارہا ہے یا زبردستی مسلط کیاجارہا ہے، وہ سیکولرازم ہے جس کے ذریعے مسلمانوں میں موجود تھوڑی بہت اسلامی اقدار اور اخلاقیات سے ان کی وابستگی کو بھی مٹادینے کی کوشش کی جارہی ہے۔ آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل یہ بات ناقابل فہم تھی اور کوئی تصور نہیں کرسکتا تھا کہ پاکستان میں سیکولرازم کی بات کی جائے گی، سعودی عرب میں تعلیم کو جدید بنانے کے نام پر اسلامی اثرات سے پاک کرنے کی بات کی جائے گی، مصر میں جامعۃ الازہر کے کردار کو ختم کرنے کی بات کی جائے گی۔ چوتھائی صدی پہلے یہ سب کچھ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا، لیکن آج دنیائے اسلام کے ہر ملک میں یہی کچھ ہورہا ہے۔ مجھے کئی ملکوں میں براہ راست جاکر مشاہدہ کا اتفاق ہوا ہے۔ جو باتیں آج کل پاکستان میں تعلیم کے بارے میں کہی جاتی ہیں، بعینہٖ وہی مصر کی جامعۃ الازہر میں بھی کہی جارہی ہیں۔ جن ’’دلائل‘‘ کا سہارا لے کر پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نصابات سے اسلامی عناصر کو نکالا جارہا ہے، وہی ’’دلائل‘‘ عرب دنیا میں دہرائے جارہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی نسخہ ہے جومختلف زبانوں میں لکھ کر مختلف ملکوں میں بھیجاجارہا ہے۔ انہی ’’دلائل‘‘ کی بازگشت خالص اسلامی اداروں میں بھی سنی جارہی ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۲۰)
مغرب کا مقتدر سیکولراور مذہبی طبقہ اسلام دشمنی میں متحد
مغرب کی اسلام دشمنی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں:
’’یہ وہ صورت حال ہے جس میں ہمیں اپنے موقف کا تعین کرنا ہے۔ اس کام میں بہت سے مشکل مقامات بھی آتے ہیں۔ وہ مشکل مقامات فوری توجہ اور فیصلہ کا متقاضی ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے جس میں مسلمان فی الحال کمزوری یا صرف نظر سے کام لے سکتے ہیں؟ کون سے معاملات ہیں جن میں ایک لمحے کے لیے بھی صرفِ نظر نہیں کیاجاسکتا یا کمزوری نہیں دکھائی جاسکتی؟ ان سب باتوں کا ایک سنجیدہ ، متوازن، غیر جذباتی اور خالص علمی انداز میں جائزہ لینا ضروری ہے۔ لیکن مسلمان تو اس کے لیے شاید تیار ہوجائیں، کیا اہل مغرب بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ یہ طے کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں او ریہ انتہائی سفاہت کی بات ہے، میں اس کو انتہائی بے وقوفی کی بات سمجھتا ہوں کہ اسلام اور مغرب کے درمیان جو دشمنی موجودہ دور میں نظر آتی ہے، یہ ماضی قریب کے کچھ واقعات کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دشمنی محض ماضی قریب کے چند واقعات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ دشمنی خالص مسیحی دور میں بھی رائج تھی، جب یورپ کی سرزمین پر خالص مسیحی حکومت قائم تھی۔ جب پوپ اور کرسچن رومن ایمپائر ، ہولی رومن ایمپائر کا زمانہ تھا، اس وقت بھی یہ دشمنیاں زور وشور سے قائم تھیں۔ اس دشمنی میں جو شدت صلیبی جنگوں کے زمانے میں تھی، وہ شدت آج بھی موجود ہے۔ صلیبی جنگوں کے حوالے آج بھی کبھی کبھی مغربی قائدین کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں۔ یہ مخالفت آج کے خالص عقلی اور سائنسی دور میں بھی جاری ہے، استعماری دور میں بھی جاری رہی اور پھلتی پھولتی رہی۔ جمہوریت، عدل ، مساوات اور احترام آدم کے نعروں کی گونج میں بھی مخالفت کی یہ لے بڑھ رہی ہے۔ یہ مخالفت ظاہر ہے کہ خالص نسلی انداز کی ہے۔ یہ ایسی مخالفت ہے جس میں مذہبی یورپ اور سیکولریورپ، مذہبی مغرب اور سیکولر مغرب دونوں متفق الرائے چلے آرہے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہبی اندازرکھتے ہیں، کچھ لوگ خالص سیکولر انداز کے حامل ہیں۔ لیکن مسلمانوں سے مخالفت اور دشمنی میں دونوں برابر ہیں۔‘‘
اسلامی ریاست کا مزاج۔۔۔عدل و رحمت
اسلامی ریاست کے مزاج پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پاکیزہ اور مطہر فکرکا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:
’’شریعت نے اپنے کو رحمت قرار دیا ہے۔ کوئی ایسا قانون ، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا تصور جو رحمت کے اس تصور کے خلاف ہو، جس میں رحمۃ اللعالمین کے پیغام رحمت کا یہ تصور نہ جھلکتا ہو، وہ اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ آج مسلم ممالک میں کتنے نظام ہیں، ملازمتوں کے،غیر مسلموں سے ڈیل کرنے کے، غیر ملکیوں سے معاملہ کرنے کے جن میں رحمت کا یہ تصور موجود نہیں ہے۔ رحمت کا یہ تصور عدل کے باب کا پہلا درجہ ہے۔ عدل تو لازمی ہے ہی، عدل تو بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور عدل کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک سطح تو وہ ہے جو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو عدل قانونی یا عدل قضائی ہے۔ دوسری سطح وہ ہے جو افراد کی ذمہ داری ہے۔ عامۃ الناس کی ذمہ داری ہے، وہ عدل حقیقی ہے اور عدل حقیقی کے بعد احسان اور رحمت کے درجات آتے ہیں۔ اسلامی ریاست کا مزاج یہ ہونا چاہے کہ عدل کے لازمی اور قانونی تقاضے تو ہر صورت میں پورے ہوں۔ اس کے بعد ریاست کی پالیسیوں میں ریاست کے رویوں میں ، ریاست کے کارپردازوں کے مزاج میں احسان اور رحمت کے تصورات جھلکتے ہوں۔ مثال کے طور پر بین الاقوامی معاملات میں دنیا کی مظلوم اقوام کی تائید، دنیا کے محروم انسانوں کی مدد، خاص طور پر محروم اور مظلوم مسلمانوں کی مدد ریاست کی پالیسی ہونی چاہیے۔ بالادست غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ مل کر کمزور اور نہتے مسلمان عوام کا قتل عام کرنا کسی بھی اعتبار سے اسلامی شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت سے بغاوت تو کہاجاسکتا ہے، اسلامی شریعت پر عملدرآمد کے تقاضوں سے یہ رویہ کوسوں دور ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۳۶۔۵۳۷)
اسلامی تہذیب کا ایک اہم وصف۔۔۔تسلسل
اسلامی تہذیب کے تسلسل پر اس انداز میں روشنی ڈالتے ہیں:
’’اسلامی تہذیب اور اسلامی شریعت کو ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم نہیں کیاجاسکتا۔ اسلامی شریعت ایک تسلسل ہے، اسلامی تہذیب ایک تسلسل سے عبارت ہے۔ اسلامی تہذیب کی تشکیل میں ماضی کے تمام علمی اور فکری ذخیرے سے گہرا تعلق اور وابستگی ناگزیرہے۔ اسلامی شریعت میں تو فقہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ شریعت کے ان احکام کا علم جو قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہیں۔ لہٰذا قرآن و سنت سے براہ راست، مسلسل اور ناقابل شکست وابستگی تو اس عمل کا بنیادی اور ناگزیر حصہ ہے۔ قرآن و سنت سے وابستگی کسی خلامیں نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کم از کم ان کے طرزعمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید قرآن آج نازل ہوا ہے، سنت کا علم آج ان کو ہوا ہے اور وہ اپنی کم علمی اور سادہ لوحی سے یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر انہیں کسی حدیث کا علم ہوگیا ہے یا قرآن کی کسی آیت کا علم ہوگیا ہے تو ایسا اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ نہ ماضی میں کسی نے قرآن اور حدیث کو سمجھا، نہ ماضی قریب میں کسی نے سمجھا۔ آج پہلی بار انہی کی سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن کریم یا سنت کیا کہتے ہیں۔ اس طرزعمل سے فائدہ تو شاید ہی ہوتا ہو، قباحتیں بہت پیدا ہوتی ہیں، اسلامی روایت کے تسلسل میں خلل پڑتا ہے۔ اسلامی روایت کا تسلسل برقرار رکھنا اسلامی تہذیب کے لیے ناگزیر ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۴۰)
تقلید، ایک دودھاری تلوار
اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’یہاں تقلید کا سوال بھی آجاتا ہے جو ایک دو دھاری تلوار ہے۔ تقلید بعض پہلوؤں میں، بعض اعتبارات سے ناگزیر ہے جہاں تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔ مثلاً میں سائنس کا علم نہیں رکھتا، میں فزکس سے واقف نہیں ہوں، اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق سائنس سے ہو اور مجھے اس کے بارہ میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو میں بغیر کسی دلیل کے محض اعتماد کی بنیاد پر کسی ایسے سائنسدان کی رائے کی پابندی کروں گا جس کے علم اور کردار پر مجھے اعتماد ہو۔‘‘ (ایضاً )
مستقبل کی نقشہ گری کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں:
’’لیکن یہ تقلید کی ایک سطح ہے۔ اس کا تعلق انسانوں کی روزمرہ زندگی سے ہے، اس کا تعلق انسانی معاشرے کی اسلامی اساس اور اس کے تسلسل سے ہے۔ لیکن مستقبل کی تشکیل ، مستقبل کی نقشہ کشی ماضی کے تسلسل کی ضمانت کے ساتھ ساتھ جس چیزکا تقاضا کرتی ہے، وہ نئے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، نئے مسائل کا حل کرنا ہے، نئی مشکلات کو دور کرنا ہے، نئے سوالات کا جواب دینا ہے۔ ان سب امور کے لیے نئے مسائل کے حل کے لیے جرات مندانہ اجتہاد ناگزیر ہے۔ لہٰذا ماضی سے تسلسل برقرار رکھنے کے لیے تقلید اور مستقبل کی نقشہ کشی کے لیے اجتہاد ایک اساسی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا توازن ہونا چاہیے کہ نہ تقلید کے تقاضے مجروح ہوں جس کے نتیجے میں تسلسل کا عمل اختلال کا شکار ہوجائے اور نہ اجتہاد کے تقاضے مجروح ہوں جس کے نتیجے میں مستقبل کی نقشہ کشی مشکل ہوجائے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۴۱)
عالمگیریت اور عالمی فقہ
فقہ پر گفتگو کرتے ہوئے غازی صاحبؒ فرماتے ہیں:
’’آج ہم ایک نئی فقہ کی تشکیل کے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ فقہ وہ ہے جس کو میں کئی بار اپنی گفتگوؤں میں cosmopoliton fiqh یا globalized fiqh کے نام سے یاد کرچکا ہوں۔ الفقہ العولمی بھی اس کو کہا جاسکتا ہے۔ آج کا دور بین الاقوامیت کا دور ہے۔ اسلام کی بین الاقوامیت کا صحیح اور مکمل مظاہرہ آج کے دور میں ہوگا۔ ماضی کا دور مختلف علاقوں اور مختلف ثقافتوں کے درمیان باہمی اتفاق کا دور تھا۔ جب اسلامی ریاست ایک بڑی ریاست تھی، بنی عباس کے دور میں یا سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو وہاں بھی اصل نوعیت یہ تھی کہ یہ مختلف خود مختار مسلم مملکتوں یا ریاستوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا نیم وفاق تھا۔ عملاً یہی صورتحال تھی۔ آج کی زبان میں اس کو یہی کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے اس صورتحال کے تقاضے کچھ اور تھے۔ آج جس نئے نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ مستقبل میں کسی مسلکی فقہ کے بجائے ایک نئی فقہ عولمی کی ضرورت ناگزیر محسوس ہوتی ہے۔ مغربی عالمگیریت کا مقابلہ اسلامی عالمگیریت کے بغیر نہیں کیاجاسکتا۔ جدید عالمگیریت کے مسائل سے عہدہ برآہونے کے لیے اسلامی عالمگیریت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔
اسلامی عالمگیریت کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک عالمگیر فقہ کی تدوین نو کی جائے۔اس کے لیے فقہ سیر کی تشکیل جدید سب سے پہلا قدم ہے۔ تجارتی اور مالیاتی فقہ کی تدوین نو جس پر خاصا کام ہورہا ہے۔اس میدان میں ناگزیر ہے۔ ان سارے میدانوں میں تشکیل نو اور بالخصوص فقہ کی تدوین نو کے لیے ہمیں قدیم اسلامی روایت سے انتہائی گہری اور مضبوط وابستگی کے ساتھ ساتھ مشرق و مغرب کے تمام مفید تجربات سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۴۵)
مشرق و مغرب سے گہری اور ناقدانہ واقفیت
اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’مغرب اور مشرق دونوں کے تجربات کیا ہیں؟ کیا رہے ہیں؟ علوم کے میدان میں بھی، صنائع اور فنون کے میدان میں بھی، ان سب سے گہری اور ناقدانہ واقفیت دنیائے اسلام کے مستقبل کے لیے ناگزیرہے۔ مغربی تہذیب بہت جامع اور بھرپور تہذیب ہے۔ مغربی تصورات میں کچھ پہلو مفید ہیں، کچھ پہلو ہمارے لیے غیر ضروری ہیں۔ کچھ پہلو اسلامی شریعت اور عقیدے کی روشنی میں ناقابل قبول ہیں، کچھ پہلو شدید گمراہیوں پر مبنی ہیں۔ یہ گمراہیاں جنہوں نے دنیائے اسلام میں بہت سے ذہنوں کو متاثر کیا ہے، وہ کیا ہیں؟ یہ گمراہیاں بے شمار ہیں۔ یہ فکر و فلسفہ کے میدان میں بھی ہیں ، تعلیم اور مذہبیات کے میدان میں بھی ہیں۔ مذہبیات کے میدان میں بالخصوص کتب مقدسہ کی نوعیت کیا ہے؟ کتب مقدسہ یا نصوص مقدسہ کی تعبیر و تفسیر کے بارے میں بہت سی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں جن سے دنیاے اسلام میں بھی بعض لوگ متاثر ہورہے ہیں۔ یہ گمراہیاں قانون اور سیاست کے میدان میں بھی ہیں ۔ معاشیات کے باب میں بھی ہیں، نفسیات اور اخلاقیات سے بھی ان کا تعلق ہے ، معاشرت و معیشت میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔
جب تک ان تمام امور کا الگ الگ جائزہ نہیں لیاجائے گا اور ان گمراہیوں اور غلط تصورات پر عقلی تنقید کرکے ان کا برسرغلط ہونا ثابت نہیں کیاجائے گا، اس وقت تک فکر اسلامی کی تشکیل نو اور فقہ اسلامی کی تدوین نو کا عمل دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں مشکل کام ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۴۶)
ہردور کے اہم فکری مسائل
ایک اور اہم نکتے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے غازی صاحبؒ فرماتے ہیں:
’’یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر دور میں بعض اہم فکری مسائل اور تہذیبی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے زیادہ اہمیت اختیار کرلیتے ہیں اور پھر ساری فکری اور تہذیبی سرگرمی انہی کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر بیسویں صدی کے نصف اول میں جو فکر تھی، اسلامی بھی اور اسلام کے دائرے سے باہر بھی، وہ ریاست و سیاست پر مرتکز تھی۔ اس زمانہ کے تمام بڑے بڑے مفکرین اسلام اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست پر لکھ رہے تھے۔ اس لیے اس دور میں یہی بڑا مسئلہ تھا۔ ریاست کی حقیقت اور ماہیت پر غور و خوض ، اسلامی ریاست کی تشکیل ، یہ مسائل فکر اسلامی کے نمایاں مسائل تھے۔
بیسویں صدی کے نصف دوم میں ریاست اور سیاست کی مرکزیت کم ہوگئی اور اقتصاد و مالیات کی مرکزیت نمایاں ہوگئی، چنانچہ فکر اسلامی کا اہم مضمون سیاست اور ریاست کے بجائے اقتصاد و مالیات کے مضامین قرار پائے۔ آئندہ پچاس سال یا کم و بیش ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیریت اور اس کے مسائل، گلوبلائزیشن کے مسائل فکر کے بنیادی مسائل ہوں گے اور دنیا کے مفکرین اور اہل علم کی توجہ ان معاملات کی طرف رہے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ، خاص طور پر آئندہ چند عشروں میں یہ ہے کہ عالمگیریت کی فکری اور اخلاقی اساس کا تعین کرنے میں دنیا کی رہنمائی کریں۔اخلاق کی عالمگیر اور متفقہ اساس کی نشاندہی کریں اور مذہب اور معاشرہ، مذہب اور تہذیب، مذہب اور ریاست، مذہب اور معیشت کے اس تعلق کو دوبارہ یاد دلائیں جو دنیا نے بھلا دیا ہے۔ اس تعلق کو مغرب نے بھلایا تو اس کے کچھ اسباب بھی تھے۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۴۷۔۵۴۸)
مغرب کی مذہبی اور سیکولرطاقتوں کا مشترکہ ہدف
مغرب کی گمراہیوں کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’مغرب کی نظرمیں اصل مسئلہ ان کی عسکری اور اقتصادی قوت کے تحفظ کا تھا۔ اس عسکری اور اقتصادی قوت کا تحفظ کرنے اور اسے فروغ دینے کے عزائم اور عمل میں جب شدت پیدا ہوئی تو اہل مغرب نے محسوس کیا کہ اخلاق اور مذہب کے قواعد ان عزائم کے راستہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے ان تمام علائق اور رکاوٹوں کو دور کردیا اور یوں اخلاق اور مذہب کا تعلق سیاسی اور اقتصادی زندگی سے کٹ گیا۔ وہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عسکری اور اقتصادی قوت کو محفوظ بنائیں، اس کے تسلسل کو یقینی بنائیں اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقصادی حریف بننے سے روکیں۔ آج وہ دنیائے اسلام کو نہ اقتصاد کے میدان میں اپنا حریف بننے دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ عسکری میدان میں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اہل مشرق کو مغرب کی پیروی پر آمادہ رکھا جائے اور ایسا ذہن بنایاجائے کہ اہل مشرق اپنے نظام اور تہذیب کے مستقبل سے مایوس ہوجائیں۔ آج اگر ہمارا نوجوان اپنے مستقبل سے ، اپنے ملک کے مستقبل سے، تہذیب کے مستقبل سے مایوس نظر آتا ہے یا بے یقینی کا شکار نظر آتا ہے تو اس کے اسباب گزشہ ڈھائی تین سو سال کی مغرب کی تاریخ میں تلاش کرنے چاہئیں۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۴۸)
امت مسلمہ کا بین الاقوامی کردار۔۔۔اخلاق اور کردار کی بنیاد پر
محاضرات شریعت کے عنوان سے اپنے خطبات کے اختتامی کلمات میں فرماتے ہیں:
’’امت مسلمہ کے بین الاقوامی کردار کے جہاں اقتصادی سیاسی اور قانونی پہلو ہیں، وہاں اخلاقی، مذہبی اور انسانی پہلو بھی ہیں۔ آج بین الاقوامی معاملات میں اخلاق اور مذہب کا حوالہ اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا گزشتہ تین چار سو سال سے جس بین الاقوامی لین دین اور بین الاقوامی قانون سے مانوس ہے، وہ بڑی حد تک اخلاق اور مذہب سے لاتعلق ہے۔ اس تعلق کو دوبارہ استوار کرنا اور بین الاقوامی تعلقات کو اخلاق اور کردار کی بنیاد پر تعمیر کرنا پوری انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے اوراس ضرورت کی تکمیل کا سامان اسلامی شریعت اور اسلامی تہذیب ہی کے ذریعے کیاجاسکتا ہے۔
آج مادیات اور روحانیات کے مابین وہ علمی اور فکری بُعد باقی نہیں رہا جو گزشتہ ہزار ہا سال سے موجود تھا۔ آج فلسفہ اور سائنس ایک دوسرے کے قریب آرہے ہیں۔ مادہ اور روح ، matter اور spirit کے درمیان جو فرق اور امتیاز ماضی میں کیاجاتا تھا، وہ ختم ہورہا ہے۔ آج سائنس کے برتر اصولوں کو سمجھے بغیر سائنس کی مزید ترقی کے راستے بند نظر آتے ہیں۔ یہ برتر اصول فلسفہ اور حکمت کی سرحد پر نہیں بلکہ ان کی حدود کے خاصا اندر واقع ہیں۔ ایک سطح پر فلسفہ اور مذہب کے مدعیان میں حکماء اور علماء دونوں کا اجتماع ہوجاتا ہے۔ گویا فلسفہ اور مذہب میں قدیم علماء اور منطقیوں کے قول کے مطابق عموم خصوص من وجہ کی نسبت قائم ہوجاتی ہے۔ اب سائنس بھی ان حدود میں داخل ہورہی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور پھر آنے والا ہے جب فقیہ اور مفسر حکیم بھی تھا اور سائنس دان بھی تھا۔‘‘ (ایضاً صفحہ ۵۵۱)
عام ریاست اور اسلامی ریاست میں اہم فرق
ڈاکٹر غازی صاحبؒ عام ریاست اور اسلامی ریاست میں ایک اہم فرق پر اپنے منفرد انداز میں اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:
’’مدینہ کی ریاست اور بقیہ ریاستوں میں ایک دوسرا بڑا اہم فرق یہ ہے کہ جب ریاست بنتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ گویا ریاست مقصد ہے اور قانون اس کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں اس کے برعکس ہے۔ یہاں ایک قانون الہٰی نازل ہورہا تھا۔ ایک شریعت دی جارہی تھی۔ اس شریعت کے بعض احکام مکہ مکرمہ میں نازل ہوچکے تھے۔ اس شریعت کے نفاذ اور تحفظ کے لیے ریاست کی ضرورت تھی۔ یہاں قانون اصل چیز تھی اور ریاست ذریعہ تھی۔ لہٰذا شریعت اصل مقصود ہے اور ریاست اس کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں ریاست مقصود نہیں ہے۔اسلام میں ریاست حصول مقصد کا ایک اہم اور ضروری وسیلہ ہے۔ لہٰذا اسلام میں ریاست کا درجہ بعد میں ہے، شریعت کا درجہ پہلے ہے۔‘‘ (محاضرات سیرت صفحہ ۳۳۳)
رحمت اور عدل لازم و ملزوم
رحمت اور عدل پر اسلام کے حقیقی تصور کی ترجمانی اورمغربی قانونی تصور پر بے لاگ تبصرہ یوں فرمایا:
’’رحمت اور عدل دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ عدل کو نظر انداز کرکے رحمت نہیں ہوسکتی۔اگر عدل کے تقاصے کو نظر انداز کرکے رحمت کا رویہ اپنایاجائے گا تو وہ نام نہاد رحمت رحمت نہیں ہوگی بلکہ ظلم ہوگا۔ رحمت اور عدل دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو شخص رحم نہیں کرتا وہ خود بھی رحم کا مستحق نہیں ہے۔ ’’من لا یرحم لا یرحم‘‘ یہ رحمت للعالمین نے ہی فرمایا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، وہ خود بھی رحم کا مستحق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک آدمی دس آدمیوں کو قتل کردے۔ مقتولین تو رحمت اور شفقت کے مستحق نہ ہوں اور قاتل رحمت کا مستحق ہوجائے۔ یہ انسانیت کے خلاف بغاوت ہے اور خود ایک مکروہ انسانی جرم ہے کہ مجرم اور قاتل کو برابر اور یکساں طور پر رحمت کا مستحق سمجھا جائے۔ اس مظلوم کو، اس کے گھر والوں اور بچوں کو تو شفقت اور رحم کا مستحق نہ مانا جائیاور شفقت، نرمی، قانونی موشگافیوں، انسانیت ہر چیز کو مجرم کی خدمت اور دفاع کے لیے وقف کردیاجائے۔ یہ خلط مبحث اور بے اعتدالی اہل مغرب ہی کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی متوازن اور اعتدال پسند شریعت اس سے بری ہے۔ یہ عدم توازن اور مجرم دوستی اسلام کے تصور رحمت کے خلاف ہے۔ اسلام اس طرح کی رحمت کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ لہٰذا عدل اور رحمت دونوں ایک چیز ہیں۔ عدل کا تقاصا رحمت اور رحمت کا تقاضا عدل ہے۔‘‘ (محاضرات فقہ صفحہ ۳۹۵)
عورتوں کے حقوق ۔۔۔اسلام کا حسن اور جدید تہذیب کا مکروہ پن
عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ڈاکٹر غازی صاحبؒ جدید تہدیب کے علمبردار برطانیہ کے قانون وراثت پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’انگلستان میں آج ۲۰۰۴ میں بھی primogentiture کا اصول رائج ہے۔ اس اصول کے معنی یہ ہیں کہ وراثت پر سب سے بڑے بیٹے کا حق ہو۔ وہاں جائداد کی مالیت اگر ایک خاص حد سے زائد ہوتو اس کا کوئی اور رشتہ دار یا فردِ خاندان وارث نہیں ہوسکتا سوائے سب سے برے بیٹے کے۔ اس اصول کے تحت سب سے بڑا بیٹا ہی ساری جائداد کا وارث ہوتا ہے اور بقیہ سب ورثا محروم رہتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انگلستان کے اس اصول پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ عورتوں کے حقوق کے علمبردار بھی خاموش ہیں۔کم سے کم میں نے کسی مغربی یا مشرقی خاتون کے بارہ میں کبھی یہ نہیں سناجس نے اس پر اعتراض کیا ہو کہ یہ انصاف کے خلاف اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔مجھے نہیں معلوم کہ شرعی احکام کے خلاف اور عورتوں کے خود ساختہ حقوق کے حق میں روزانہ مظاہرے کرنے والی خواتین اس پر کیوں خاموش رہتی ہیں۔یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ بڑی بڑی جائدادوں اور جاگیروں میں سارے کا سارا ورثہ صرف بڑے بیٹے کو ملے گا، لیکن اس میں نہ بیوی کو ملے گا، نہ بہنوں کو ملے گا، نہ بیٹیوں کو ملے گا اور نہ ماں کو کچھ ملے گا، بلکہ سب کچھ بڑے بیٹے کو ملے گا۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ چھوٹے بیٹے کو کیوں نہیں ملے گا۔ بہنوں کو کیوں نہیں ملے گا۔یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اگر بیٹا نہ ہو، بھائی، باپ اور چچا بھی نہ ہو، چچا زاد بھائی یا اس کا بیٹا بھی نہ ہو تو پھر نواسے کو ملے گا۔ بیٹیوں کو پھر بھی نہیں ملے گا۔ اب سوائے اس کے کہ یہ ایک سراسر دھاندلی اور ظلم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ شریعت نے ایسا کوئی ظالمانہ حکم نہیں رکھا۔ وراثت کے احکام لازمی طور پر واجب التعمیل ہیں اور مرنے والے کی موت کے فوراً بعد ہی اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔‘‘ (محاضرات فقہ صفحہ ۴۴۹)
سطور بالا سے بخوبی اندازہ کیاجاسکتا ہے کہ ڈاکٹر غازی کو اللہ تعالیٰ نے علمی رسوخ، فکری سلامتی، بیدار اور دردمند دل ،سلاست بیانی اور ابلاغ کی قوتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جدیددجالی دور میں اسلام کی صاف، شستہ، صحیح اور معتدل و متوازن ترجمانی کا جو ملکہ اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سعید بندے کو دیا تھا، اس بدترین زوال کے دور میں اسے ہم اسلام کا معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں۔خاص طور پر فکری سلامتی، توازن اوربے مثال قوت ابلاغ انہیں بیسویں اور اکیسویں صدی کے تمام مسلم مفکرین میں نمایاں ترین اور ممتاز ترین مقام عطا کرتی ہے۔ اس خاص پہلو سے وہ واقعتاً قدرت کا ایک شاہکار اور ماسٹر پیس تھے۔ مغربی سائنس و فلسفے کے دجالی دور کے ان بدترین اندھیروں سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آج قدرت کے ایسے ہی شاہکاراور ماسٹر پیس کی شدید ضرورت تھی ۔ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ نوع انسانی کی یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والاعلم و فکر اور قوت ابلاغ کایہ عظیم شاہکار ۲۶ ستمبر ۲۰۱۰ کو ان سے واپس لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔
سلسلہ محاضرات: مختصر تعارف
ڈاکٹر علی اصغر شاہد
استاذی ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ خالص مدارس عربیہ سے فیض یافتہ تھے۔ عصری تعلیم کے لیے کبھی بھی کسی سکول، کالج، یونیورسٹی میں نہیں گئے، بلکہ علوم نبوت کی برکت سے پرائیویٹ طور پر عصری علوم میں ممتاز کامرانیاں حاصل کیں۔ دورہ حدیث شریف کاآخری امتحان جامعہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی سے مکمل کیا۔ اس وقت طلبہ کی اکثریت پشتو زبان بولنے والوں کی ہوتی تھی تو تدریس بھی پشتو زبان میں ہوتی تھی۔ جب استاذ ی ڈاکٹر صاحبؒ نے دورہ حدیث شریف میں قدم رکھا تو ان کے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ ’’ محمود‘‘ آپ کو پشتو زبان بولنا ، سمجھنا نہیں آتی۔ آپ کیا کریں گے؟‘‘ فوراً بلاتاخیر اپنے عظیم استاذ سے عرض کیا کہ حضرت! آپ تدریس کے لیے عربی زبان کو اپنا لیں تو انہوں نے بشاشت اور خوشی سے قبول فرما کر اس کو عملاً نافذ کر دیا۔ اس طرح آخری سال دور ہ حدیث کی تعلیم کو قرآن حکیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل جنت کی زبان عربی میں مکمل کیا۔ میری اس تحریر سے استاذی ڈاکٹر صاحبؒ کی شان میں اضافہ تو نہیں ہوگا، مگر امید ہے کہ ان کے تذکرہ کی وجہ سے میری تحریر کی شان دوبالا ہو جائے گی۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابتؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ لکھتے ہوئے فرمایا:
ما ان مدحت محمدا بمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد۔
’’میں نے اپنے اس مقالہ کے ساتھ حضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنے مقالہ کی تعریف کر لی ہے‘‘۔
ڈاکٹر صاحب علمی اعتبار سے اتنے عظیم اور بلند تر تھے کہ الفاظ میں بیان کرنا میرے جیسے بے بضاعت انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس موضوع پر بھی لب کشائی فرماتے تھے اس کے متعلق احساس ہوتا تھا کہ اب اس عنوان کی تمام جہات کو اپنی انتہا پر پہنچا کر ہی یہ سمندر کی موج واپس پلٹے گی۔ اس علمی بہاؤ میں جس شان کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہی ان میں صاف نظر آیا کرتی تھی۔ ارشاد الٰہی ہے: انما یخشی اللّٰہ من عبادہ العلماء (فاطر۳۵: ۲۸) ’’بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں‘‘۔ علم کے جس موضوع کو بھی شروع فرماتے تھے، اس کے ہمہ پہلوؤں کو خوب اجاگر کرتے۔ ان کی اپنی کتاب ’’ محاضرات قرآنی‘‘ جو مئی ۲۰۰۸ء میں شائع ہوئی اس کے پیش لفظ کے آغاز میں ہے:
’’ قرآن کریم ، تاریخ وتدوین قرآن کریم اور علوم القرآن کے چند پہلوؤں پر یہ خطبات اپریل ۲۰۰۳ء میں خواتین مدرسات قرآن کے روبرو دیے گئے ، ان خطبات کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے میری بہن محترمہ عذرا نسیم فاروقی کو ہوا۔ جو اگرچہ عمر میں مجھ سے کم لیکن دینی حمیت، اخلاص اور للٰہیت میں مجھ سے بہت آگے اور میرے جیسے بہت سوں کے لیے قابل رشک ہیں‘‘ (محاضرات قرآنی: ص:۷)
کہ قرآن کریم کے متعلق ان محاضرات میں انتہائی وقیع اور عمدہ معلومات ہیں۔ کتاب میں بارہ خطبے شامل ہیں جن میں قرآن کے اکثر علوم پر مدلل گفتگو ہے۔ پہلاخطبہ ’’ تدریس قرآن مجید ایک منہاجی پہلو ‘‘ کے عنوان پر ہے۔ دوسرا خطبہ ’’قرآن مجید: ایک عمومی تعارف‘‘، تیسرا خطبہ ’’تاریخ نزول قرآن مجید‘‘، چوتھا خطبہ ’’جمع وتدوین قرآن مجید‘‘، پانچواں خطبہ ’’علم تفسیر: ایک تعارف‘‘، چھٹا خطبہ ’’تاریخ اسلام کے چند عظیم مفسرین قرآن‘‘، ساتواں خطبہ ’’مفسرین قرآن کے تفسیری مناہج‘‘، آٹھواں خطبہ ’’اعجاز القرآن‘‘، نواں خطبہ ’’علوم القرآن: ایک جائزہ ‘‘، دسواں خطبہ ’’ نظم قرآن اور اسلوب قرآن‘‘، گیارھواں خطبہ ’’قرآن مجید کا موضوع اور ا س کے اہم مضامین‘‘، بارہواں خطبہ ’’ تدریس قرآن مجید دورجدید کی ضروریات اور تقاضے‘‘ کے عنوان سے معنون ہے۰
مذکورہ خطبات مختصر نوٹس کی مدد سے زبانی دیے گئے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی ذہانت اور علمی وجاہت پر دال ہیں۔ نمونہ کے طور پر ان خطبات میں ایک اقتباس یہ ہے:
’’ اگر آپ نے بطور مدرس قرآن درس کے پہلے دن لٹھ مارنے کے انداز میں یہ کہہ دیا کہ اے فلاں فلاں لوگو! تم شرک کاارتکاب کررہے ہو اور اے فلاں فلاں لوگو! تم بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو اور تم ایسے ہو اور تم ایسے ہوتو اس سے نہ صرف ایک شدید رد عمل پیدا ہوگا، بلکہ اس کے امکانات بہت کمزور ہو جائیں گے کہ آپ کامخاطب آپ کے پیغام سے کوئی مثبت اثر لے۔ اس انداز بیان سے مضبوط گروہ بندیاں تو جنم لے سکتی ہیں، کوئی مثبت نتیجہ نکلنا دشوار ہے۔‘‘ (محاضرات قرآنی : ص۳۴)
مذکورہ بالا عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ مدرس اپنے درس کے ذریعے امت میں اتحاد پید اکرنے اور گروہ بندیوں سے محفوظ رکھنے کی کس طرح سعی کر سکتاہے۔ درس قرآن تعلیمات قرآن کے عین مطابق ہو، اخلاص نیت سے ہو، پھر اس درس سے باہمی عداوت، بغض، عناد اور حسد جیسی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور تعصب وعصبیت جڑ سے اکھڑ جائیں گی۔ ان خطبات سے عامی اپنی اہلیت کے مطابق آسانی سے کثیر فوائد حاصل کرکے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیم کے مطابق استوار کر سکتا ہے، رضاے الٰہی حاصل کر سکتا ہے، دینی و دنیوی کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ علما بھی ان خطبات سے استفادہ کر کے اپنے علم میں رسوخ پیدا کر سکتے ہیں۔
جس طرح محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن، تاریخ قرآن مجید اور تفسیر سے متعلق موضوعات پر خطبات آئے، اسی طرح محاضرات حدیث میں علوم حدیث، تاریخ تدوین حدیث اور مناہج محدثین پر بارہ خطبات بہت ہی اہم ہیں۔ ان محاضرات کی اصل مخاطب خواتین تھیں جو خالص اہل علم تھیں۔
محاضرات کی تیسری جلد فقہ اسلامی کے اہم پہلوؤں پر با رہ خطبات پر مشتمل ہے۔ فقہ اسلامی ایک بحرناپیدا کنار ہے جس کی وسعتوں ایک جلد کیا، بیسیوں جلد وں میں سمیٹنا بھی ممکن نہیں۔ ہمارے اسلاف نے فقہ کے علوم پر ان گنت کتب تحریر فرمائی ہیں۔ اس جلد میں فقہ اسلامی کے اہم مضامین، بنیادی مباحث،اساسی تصورات اور اہم پہلوؤں کو آسان زبان میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو پیش نظر ر کھ کر بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فقہ اسلامی کا اردو زبا ن میں مطالعہ کرنے والے طبقہ کے لیے تین قسم کے لوگوں کو مدنظر رکھا ہے۔ اولاً شعبہ قانون ووکالت سے تعلق رکھنے والے، دوسرے وہ علما جو فقہ یا افتا کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، تیسرے یونیورسٹیوں اور جدید تعلیم کے اداروں سے وابستہ حضرات یا وہ لوگ جو فقہ اسلامی کا عمومی اور سرسری سا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف فقہ اسلامی کے طلبہ، وکلا اور قانون دان حضرات کے لیے مفید اور دلچسپ ہے بلکہ عام تعلیم یافتہ حضرات بھی اس کے ذریعے بہت سے معلومات میں فقہی معاملات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں۔
محاضرات سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، محاضرات کی چوتھی جلد ہے۔ یہ خطبات سیرت طیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبا رکہ سے نہیں بلکہ علم سیرت سے متعلق ہیں۔ سیرت طیبہ پر ہزاروں کتب موجود ہیں جو بے شمار کتب خانوں کی زینت ہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ اردو زبان میں تاریخ سیرت، تدوین سیرت اور مناہج سیرت پر نسبتاً کم مواد ہے۔ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ مغربی مستشرقین کے پیش کردہ شبہات اور اعتراضات سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور اب اس طبقہ کے اثرات قرآن حکیم،حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اسلامی اور سیرت طیبہ کے ذخائر پر عدم اعتماد تک پہنچ گئے ہیں۔ ان حالات میں فن سیرت کی ابتدائی تدوین، تاریخ اور مناہج کے بارے میں مستند معلومات کی پہلے کی نسبت انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ اس صورت حال کے مدنظر محاضرات سیرت کے خطبات پیش کیے گئے اور ان میں مشرق ومغرب سے اٹھنے والے بے شمار اعتراضات کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔
محاضرات کی پانچویں جلد محاضرات شریعت ہے۔ اس میں شریعت اسلامیہ کا جامع تعارف کروایا گیا ہے اور شریعت اسلامیہ کے عناصر اور اہم جزئیات کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسا کہ تاریخ اسلام کے مستند، معتمد اور معتبر فقہا، متکلمین اور اصحاب تزکیہ یعنی سلوک واحسان نے اسے سمجھا اور ارشاد فرمایا ہے۔ شریعت کی تعلیم وتفہیم اور اس کے قواعد وضوابط اور احکام کے بارے میں جو کج فہمیاں، غلط فہمیاں یا شکوک وشبہات پائے جاتے ہیں، اس کتاب میں انھیں دور کرنے کی بہت خوبصورت انداز میں کوشش کی گئی ہے۔ شریعت اسلامیہ کو عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے اور جامع تعارف کے ساتھ عالمگیر سطح پر امت مسلمہ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اہم موضوعات میں اسلامی شریعت کا تعارف، خصائص، مقاصد اور حکمت، امت مسلمہ اور مسلم معاشرہ، تہذیب اخلاق، تدبیر منزل ومدن، تزکیہ واحسان وغیرہ شامل ہیں۔ آخر میں ’’اسلامی شریعت کا مستقبل اور امت مسلمہ کا تہذیبی ہدف کیا ہے‘‘ کے اہم موضوع پر نہایت وقیع خطبہ ہے جس کے محاسن اور خوبیوں کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ یہ خطبات اسلام آباد اور دوحہ(قطر) کی مختلف مجالس میں پیش کیے گئے اور دوران خطبات میں وقفے لمبے اور زیادہ رہے، سامعین بھی تبدیل ہوتے رہیجس کی وجہ سے ان میں تکرار موجود ہے۔
محاضرات کی چھٹی اور آخری جلد معیشت وتجارت سے متعلق اہم خطبات پر شامل ہے۔ عصر حاضر میں معیشت وتجارت اور مالیات کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے۔ اگر معیشت وتجارت کرنے کے ذرائع صحیح اور شریعت اسلامی کے احکام کے مطابق ہیں تو ان کا انسانی ذہن پر مثبت اثر ہوتا ہے، کیونہ لقمہ حلال سے بننے والے خون میں وہ جذبات ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کی مرضیات پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لقمہ حرام سے بننے والے خون کے جذبات انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں۔ ان میں اعلیٰ ترین نافرمانی انتہائی بے حمیتی اور بے غیرتی پر منتج ہوتی ہے جس کی بین مثال عصر حاضر کا یورپ ہے۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں بین الاقوامی تجارت اور عالمی اقتصادی نظام کے مسائل کی اہمیت کے پیش نظر وقیع اور اہم خطبات پیش فرمائے ہیں جن سے انسان صحیح اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی معیشت وتجارت اور مالیاتی مسائل کے لیے صحیح سمت کا انتخاب کرکے مرضیات خداوندی کو اپنا ہدف بنا کر دارین کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔
اسلا م کے مقابل دیگر مغربی معاشی نظام، کمیونزم اور سرمایہ داری وغیرہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں۔ انسانیت قلبی سکون کی تلاش میں ہے جو دولت وحکومت یا دنیا کی کسی اور چیز سے میسر نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر کسی کو مل سکتا ہے یا اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام اور اسلام کے اصول اصول تجارت اور اصول مالیات وغیرہ میں ہی ملنا ممکن ہے۔ مغربی معیشت ایسی مشکلات میں پھنس چکی ہے جن سے نکلنے کے لیے انھیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تمام دنیا کی نظریں اس وقت ان مشکلات کے حل کی طرف لگی ہوئی ہیں۔
محاضرات کی تمام جلدوں کی تقدیم یا پیش لفظ میں ڈاکٹر صاحب نے تمام کرم فرماؤں کا شکریہ اس انداز سے ادا فرمایا کہ اس سے ان کی اپنی شخصیت میں اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم اور ضروری پہلو جس سے انسان انسانیت کی معراج پرپہنچ جاتا ہے، انتہائی نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ اہم پہلو تواضع ہے جس کا حدیث ’’من تواضع للہ رفعہ اللہ‘‘ میں ذکر ہے۔ تواضع اور انکسار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو وہ مقام عطا فرمایا جوان کے معاصرین میں سے کسی کو نہ مل سکا۔
ڈاکٹر صاحب کی دینی اور علمی خدمات محاضرات کی شکل میں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ عصر حاضر میں علوم کے اعتبا ر سے علوم نبوت کے ورثا یعنی علماے کرام اور عصر ی تعلیم کے ماہرین ڈاکٹر صاحب کے محاضرات سے انتہائی متاثر ہیں۔ آخری خطبہ یعنی محاضرات کی آخری کڑی ’’تاریخ حدیث اور صحاح ستہ کا مقام و مرتبہ‘‘ آپ نے ۲۴؍ جولائی ۲۰۰۸ء کو جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں ارشاد فرمایا جو محرم الحرام ۱۴۳۲ھ میں طبع ہوا۔ اس سے قبل یہ خطبہ ’’تحقیقات حدیث‘‘ میں بھی چھپ چکا ہے۔ مگر اس وقت میرے سامنے جو خطبہ موجود ہے، وہ خود ڈاکٹر صاحب ؒ کی طرف سے نظر ثانی و نظر ثالث شدہ خطاب ہے جس میں مجلہ ’’ تحقیقات حدیث‘‘ میں شائع شدہ مضمون پر اضافات بھی شامل ہیں۔ اس میں، جیسا کہ نام سے واضح ہے، علم حدیث کی اہمیت اور علوم حدیث اور طالبان حدیث کی خدمات عظیمہ کا تذکرہ ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبؒ کی تمام حسنات کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما کر ان کے تمام علمی محاضرات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں اپنے شایان شان مقام رفیع عطا فرمائے۔ آمین۔
’’محاضراتِ قرآنی‘‘ پر ایک نظر
حافظ برہان الدین ربانی
جہالت کی تاریکی کو علم کے نور سے بدلنے اور بھٹکتی انسانیت کو جینے کا شعور دینے کے لیے معاشرہ اور سوسائٹی ہمیشہ علم اور اہل علم کے محتاج رہے ہیں۔تغیر زماں کے ساتھ کئی اہل علم آئے اور اپنی ہمت وبساط کے مطابق اپنے علم سے روشنی کے دیپ جلاتے رہے۔ انہی قد آور شخصیات میں ایک نام ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کا بھی ہے جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ بعض لوگ اس دنیا سے بظاہر رخت سفر باندھ لیتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے ایسے کارنامے چھوڑ جاتے ہیں جن کی بدولت وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں ۔ ڈاکٹر صاحب بھی قانون خداوندی: کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَۃُ الْمَوْتِ (۳:۱۸۵) کے مطابق اس جہانِ فانی سے کوچ کرگئے، لیکن اہل علم کے لیے محاضرات کی شکل میں ایک عظیم علمی اثاثہ چھوڑ گئے ۔ محاضرات اصل میں ڈاکٹر صاحب کے مختلف مقامات پر دیے گئے لیکچرز ہیں جو اب کتابی شکل میں دستیاب ہیں۔ ان میں محاضرات قرآنی ، محاضرات حدیث ، محاضرات فقہ ، محاضرات سیرت اور محاضرات معیشت وتجارت وغیرہ شامل ہیں۔
ہم اس وقت ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے محاضرات قرآنی پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان محاضرات کے لیے تحریک ڈاکٹر صاحب کی ہمشیرہ محترمہ عذرا نسیم فاروقی نے پیدا کی اور ان خطبات کو صوتی مسجل سے صفحہ قرطاس پر بھی منتقل کیا۔زیر نظر محاضرات قرآنیات پر دیے گئے بارہ خطبات کا مجموعہ ہے جن کی ترتیب کچھ یوں ہے :
خطبہ اول : تدریس قرآن مجید: ایک منہاجی جائزہ
خطبہ دوم : قرآن مجید: ایک عمومی تعارف
خطبہ سوم : تاریخ نزول قرآن مجید
خطبہ چہارم : جمع و تدوین قرآن مجید
خطبہ پنجم : علم تفسیر: ایک تعارف
خطبہ ششم : تاریخ اسلام کے چند عظیم مفسرین
خطبہ ہفتم : مفسرین قرآن کے تفسیری مناہج
خطبہ ہشتم : اعجاز القرآن
خطبہ نہم : علوم القرآن
خطبہ دہم : نظم قرآن اور اسلوب قرآن
خطبہ یازددہم : قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین
خطبہ دو از دہم : تدریس قرآن مجید: دور جدید کی ضروریات اور تقاضے
محاضرات قرآنی اس لحا ظ سے بڑی خصوصیت کے حامل ہیں کہ اس میں قرآنیات کے حوالے سے تقریباً تمام موضوعات کا احاطہ کرنے اور طویل و دقیق موضوعات کو مختصر اور عام فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بڑی حد تک ڈاکٹر صاحب کو اس کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں محاضرات قرآنی کا مطالعہ ایک عام قاری کو دوسری بہت سی کتب سے مستغنی کرتا اور ایک محقق کے علمی سفر کے لیے راہ ہموار کرتا ہے ، وہاں ڈاکٹر صاحب کے علمی مقام ومرتبہ کو بھی اجاگر کرتاہے ۔جہاں یہ محاضرات ایک ادیب کے لیے ادب کی چاشنی اور ایک محقق کے لیے تحقیقی راہنمائی لیے ہوئے ہیں، وہیں ایک مدرس کے لیے انداز تدریس کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ ایک عام قاری بھی ان کے مطالعہ کے دوران میں کسی قسم کا ثقل اور بوجھ محسوس نہیں کرتا۔
قرآن اپنے دعویٰ ھُدًی للناس کے مطابق چونکہ تمام انسانیت کی راہنمائی کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے، اس لیے اس کا مطالعہ ایک غیر مسلم کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کسی مسلمان کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک غیر مسلم کے لیے قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
’’ایک انصاف پسند غیر مسلم اگر قرآن مجید پر نظر ڈالے گا اور قرآن مجید کی تاریخ اور انسانیت پر اس کے اثرات کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے بھی شاید اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں جس نے انسانیت کی تاریخ پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہو جتنا قرآن مجید نے ڈالا ہے۔‘‘ (ص: ۱۶)
اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے موصوف قرآن مجید کے ان اثرات کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو اس نے انسانی تاریخ پر مرتب کیے۔ قرآن نے انسانیت پر جو عظیم احسانات کیے، ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
’’نزول قرآن سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی تھی (جو کسی حد تک اب بھی پائی جاتی ہے) کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ اپنے اندر خاص قسم کے ما فوق الفطرت اثرات اور قوتیں رکھتی ہے۔ یہ غلط فہمی انسانوں میں بہت پہلے کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوگئی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہر وہ قوت جو اس کی نظر میں مافوق الفطرت حیثیت رکھتی ہے، وہ اس بات کی مستحق ہے کہ نہ صرف اس کا احترام کیا جائے بلکہ اس کی تقدیس بھی کی جائے۔ چنانچہ انسانوں نے ہر نافع اور ضار چیز کو مقدس سمجھنا شروع کردیا۔ آگے چل کر یہ احترام اور یہ تقدیس بڑھتے بڑھتے عبادت کے درجہ تک جا پہنچا۔ یوں ہوتے ہوتے ہر کائناتی قوت محترم اور مقدس قرار پاجاتی ہے، پھر اس کی پوجا کی جانے لگتی ہے اور اس کو بالآخر معبود کے درجہ پر فائز کر لیا جاتا ہے۔‘‘ (ص ۱۷)
اس قسم کے لوگوں کی قرآن کس حوالے سے راہنمائی کرتا ہے، ڈاکٹر غازیؒ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے:
’’ انسانی تاریخ میں قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسان کو یہ بتایا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، وہ تمہارے فائدے اور استعمال کے لیے پیدا کیا گیاہے: وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے ،وہ اجرام فلکی ہوں ، گرجتے بادل ہوںِ، وہ بہتے دریا ہوں، وہ چمکتے ستارے ہوں، گہرے سمندر ہوں، وہ خطرناک جانور یا دیگر مخلوقات ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔‘‘ (ص: ۱۸)
وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، ایک عام انسان اس آیت مبارکہ پر غور کرنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اگر زمین میں موجود سب کچھ میرے لیے مسخر کیا گیاہے تو بجائے اس کے کہ ان اشیا سے فائدہ حاصل کروں اور انھیں تحقیق کا موضوع بناؤں، انھیں تقدیس کا مقام دے کر ان کا خادم کیوں بن جاؤں؟ کیونکہ کسی چیز کا تقدس ہی اس چیزکے استعمال اور اس کے متعلق تحقیق میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے ۔اس بات کو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں ہی ملاحظہ کیجیے:
’’ جب آپ یہ یقین کرلیں کہ کوئی چیز آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور آپ اسے ہر طرح استعمال کر سکتے ہیں ، وہ آپ کے لیے بطور دوا کے ، بطور غذاکے، بطور علاج کے،بطور زینت کے، یا کسی بھی طرح سے آپ کے کام آ سکتی ہے تو پھر آپ اس پر تحقیق شروع کریں گے۔ اس کے ٹکڑے کریں گے، اس کے حصے بخرے الگ الگ کریں گے اور لیبارٹری میں رکھ کر اس کی تحقیق کریں گے، کیونکہ تقدیس کے ساتھ تحقیق ممکن نہیں ہے۔ تحقیق ممکن ہے امکان تسخیر کے ساتھ ۔ جس چیز کو مسخر کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ آپ اس چیزکو مسخرکر سکتے ہیں، وہی چیز آپ کی تحقیق کا موضوع بنے گی، لیکن جس چیز کے گرد تکریم و تقدیس کا ہالہ چھایا ہوا ہو، اس کی تحقیق نہیں ہوتی۔‘‘ (ص: ۱۸)
ڈاکٹر غازی مرحوم کی تائید میں ہم گزارش کریں گے کہ تاریخ عالم پر نظر رکھنے والے ہر صاحب علم پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن کے نزول سے قبل انسان کائنات کے حقائق سے کتنابے خبرتھا اور نزول قرآن کے بعد اس کے علم میں مسلسل اضافہ ہوا ہے ۔آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب قرآن کی دوسری بڑی عطا جو اس نے ایک عام انسان پر کی غالباً اس آیت : یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللّٰہِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّہَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ (حجرات:آیت ۱۳) اور حدیث مبارکہ: ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود کی روشنی میں د یکھتے ہوئے فرماتے ہیں :
’’قرآن مجید کی ایک اہم عطا جس سے پورا عالم انسانیت یکساں طور مستفید ہوا اور ہو رہا ہے انسانی وحدت اور مساوات کا وہ واضح تصور اور دو ٹوک اعلان ہے جو قرآن مجید کے ذریعہ سے پہلی بار دنیا کو عطا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل دنیا کی ہر قوم میں نسلی ، لسانی ، لونی ، جغرافیائی بنیادوں پر امتیازی سلوک اور اونچ نیچ عام تھی۔ ایسے عوامل اور عناصر کی بنیاد پر جو انسان کے اپنے اختیار میں نہ تھے انسانوں کے مابین تفریق کو ایک مستقل صورت دے دی گئی تھی ۔اقوام عالم کے مابین تفریق اور دشمنی کی بنیاد کسی فطری یا عقلی یا اخلاقی مصلحت کے بجائے رنگ و نسل، زبان اور جغرافیہ کے امتیازات تھے جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں ۔کو ئی انسان اپنی نسل خود منتخب نہیں کرتا، کوئی شخض اپنا رنگ خود پسند نہیں کرتا، کسی شخض کی مادری زبان کا انتخاب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں وہ پیدائش کے وقت ساتھ لاتا ہے ۔ ان غیر اختیاری امور کی بنیاد پر گروہوں اور قوموں کی تشکیل کو قرآن مجید ایک وجہ تعارف کے طور پر تو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ان چیزوں کو وحدت انسانی اور مساوات آدم میں مخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ انقلاب آفریں اعلان کیا کہ وحدت الٰہ کا لازمی تقاضا ہے کہ وحدت آدم کے اصول کو تسلیم کیا جائے۔‘‘(ص:۱۹)
انسان پر قرآن کے تیسرے بڑے احسان، نزول قرآن سے قبل اور بعد میں انسان اورخدا کے تعلق میں فرق کے حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ فرماتے ہیں :
’’ اسلام سے پہلے انسانوں کی مذہبی زندگی کی ساری باگ دوڑ بعض خاص طبقات کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ مذہبیات کی تاریخ کا ہر طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام سے قبل ہر مذہب میں مذہبی زندگی پر متعین گروہوں اور مخصوص طبقات کی اجارہ داری ہوتی تھی ۔ یہ اجارہ داری یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ آخرت میں گناہوں کی معافی تک کے اختیارات مذہبی طبقوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مذہبی پیشوا رشوتیں لے کر گناہوں کی معافی کے پروانے جاری کیا کرتے تھے ۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں آج بھی مذہبی پیشوا خصوصی اختیارات اور اجارہ داری کا دعوے دار ہے۔ وہ کسی بت خانہ کا پنڈت یا پروہت ہو، کسی گرجا کا پادری ہو، کوئی ربی ہو، یا کوئی اور مذہبی عہدیدار ہو، اپنے مذہب میں وہی مذہبی زندگی کا اجارہ دار ہے ، وہ اللہ تعٰا لیٰ اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں ہونے دیتا۔ کہنے کو تووہ گناہ گارانسانوں اور ان کے خالق کے درمیان سفارشی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن دراصل وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی دنیا میں ہر جگہ یہی رواج تھا، اور آج بھی یہی رواج ہے، قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرکے اعلان کیا: ادعونی استجب لکم۔ مجھے (اللہ) پکارو میں تمھاری پکار سنوں گا۔ ہر انسان جب دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو براہ راست روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچتی ہے ۔ اجیب دعوۃ الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ‘‘(ص:۲۲)
اس اقتباس کی روشنی میں ایک مسلمان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن سے دوری نے آج پھر اسے اسی گمراہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے جہان انسان نزول قرآن سے قبل ڈگمگا رہا تھا ۔ ہم زیادہ دور نہیں اپنے ملک پاکستان کے حالات پر ہی ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ایسے علماء و مشائخ کی ایک کھیپ ملے گی جن کی حیثیت ایک مذہبی اجارہ دار سے کم نہیں ۔ شاید کہ انہیں کبھی قرآن کو ہاتھ لگانے کا موقع بھی نہ ملا ہو لیکن وہ اپنے حلقہ میں مریدین کی ایک اچھی خاصی تعداد رکھتے ہیں۔ اور نسلی و صوبائی منافرت بھی کسی سے اوجھل نہیں، چاہے وہ پنجابی پٹھان کا جھگڑا ہو یا مہاجر مقامی کا نعرہ یا پھر قبائلی عصبیت ہو یہ سب کچھ ایک اسلامی ریاست میں اپنے عروج کو پہنچے ہوئے ہیں ۔ان سب کا سدباب قرآن سے تعلق قائم کیے بغیرنہیں ہوسکتا۔ورنہ قرآن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ سے شکایت پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القراٰن مھجورا۔ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبہ نمبر دو (قرآن مجید ایک عمومی تعارف) خطبہ نمبر تین(تاریخ نزول قرآن مجید) اور خطبہ نمبرچار (جمع و تدوین قرآن) میں قرآن مجید کا مکمل تعارف اور تاریخ بیان کی ہے۔اقسام وحی پر بات کرتے ہوئے وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اقسام وحی کا تفصیلی ذکر کیا ہے ۔قرآن کریم کو یک بار نازل نہ کیے جانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ فرماتے ہیں :
’’اس کتاب کے ذریعے سے ایک حقیقی اور دیر پا تبدیلی پیدا کرنا مقصود تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خلا میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک تبدیلی کی راہ نمائی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہوا قرآن کا نزول بھی جاری رہا ، اور جوں ہی تبدیلی کا عمل مکمل ہوگیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہوگیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے۔ یہ دو مختلف لیکن متوازی عمل تھے، روئے زمین پر تبدیلی کا عمل اور آسمان پر نزول کتاب کا عمل جاری تھا،دونوں ایک ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تبدیلی کا یہ عمل اسی وقت ممکن تھا جب نزول آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کرکے ہوتا۔ کسی انسان میں بھی اچانک مکمل تبدیلی نہیں آتی۔ ایسے لوگ بہت ہی شاذونادر ہوتے ہیں جو اچانک اور یک بارگی اپنے اندر ایک مکمل تبدیلی لے آئیں۔ بالفرض اگر کسی کے رویہ میں تبدیلی اچانک آبھی جائے تو پھر بھی روز مرہ کی تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔قرآن مجید کے زیر ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نمائی میں تبدیلی کا یہ عمل شروع ہوا اور تیئیس سال مسلسل جاری رہا۔ جب ضرورت پیش آئی راہ نمائی نازل ہوگئی اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آگئی۔ کسی جگہ قوانین کی تبدیلی آئی، کسی جگہ عقائد میں تبدیلی آئی اور کہیں عقائد اور کردار دونوں کو بہتر بنایا گیا۔ کہیں سابقہ انبیاء کی وہ شریعتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا تھا ان کے بنیادی عناصر دوبارہ یاد دلائے گئے ۔اس تبدیلی کو یقینی اور دیر پا بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ عمل تھوڑا تھوڑا کرکے کیا جائے۔‘‘ (ص:۶۶)
یہ تو قرآن مجید کی کیفیت نزولی کے حوالے سے بات تھی جس کا ڈاکٹرصاحب نے ذکر کیا۔لیکن اگر ہم قرآن کا مزاجِ تربیت دیکھیں تو اس میں دو اصولوں کو ہمیشہ مد نظر رکھاگیا:
(۱) قرآن مجید میں کسی ایسی معاشرتی برائی کوجو اس سوسائٹی میں سرایت کر چکی ہو، یک بارگی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ تدریجی عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس برائی سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ اور جب اس چیز کا اثر برائے نام رہ گیا یا اس برائی کو برائی سمجھنے پر طبیعتوں میں رجحان پیدا ہونے لگا تو پھر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔اس بات کے لیے شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن نے کیا طریقہ اختیار کیا، اس پر غور کرلینا کافی ہے۔
(۲) قرآن مجید میں کسی بھی بات کو منوانے کے لیے دعویٰ بغیر دلیل کے راستہ کو نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ کسی حکم کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی متعلقہ نشانیوں اور حکمتوں کا بھی ذکر کر دیا گیا اور اس کے بعد انسانی عقل کو بذات خود غوروفکر کی دعوت دی گئی ، تاکہ وہ حق بات کو زبردستی قبول کرنے کے بجائے دلی طور پر اس کے سامنے سر تسلیم خم کردے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے درج ذیل آیات پر غور وفکر کافی ہے:
لَوْ کَانَ فِیْہِمَا آلِہَۃٌ إِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ (الانبیاء: ۲۲)
’’اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہوجاتے،پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔‘‘
إِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْْلِ وَالنَّہَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِیْ الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّٰہُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْیَا بِہِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا وَبَثَّ فِیْہَا مِن کُلِّ دَآبَّۃٍ وَتَصْرِیْفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَیْْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (البقرہ: ۱۶۴)
’’آسمانوں اور زمین کی پیدائش ،رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمانوں سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانورں کو پھیلادینا، ہواؤں کے رخ بدلنا ، اور بادل، جو آسمان اور زمین کے درمیاں مسخر ہیں، ان میں عقلمندوں کے لیے قدرت الٰہی کی نشانیاں ہیں۔‘‘
بد قسمتی سے یہ دونوں مزاج ہمارے معاشرے سے مفقود ہوکر رہ گئے ہیں ۔ اپنی کوئی بات منوانے کے لیے( خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو ) تحکمانہ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی نرمی کی آمیزش تک کرنے سے گریز کیا جاتاہے۔ اور اگر کوئی اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی خلش کو دور کرنے کے لیے کسی صاحب علم سے کسی قسم کی دلیل کا مطالبہ کرے تو بجائے اس کی راہ نمائی کے اپنی علمی کمزوری کو چھپانے کی غرض سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا جاتا ہے ۔نہ جانے یہ بات کیوں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ ہمارا تجاہل عارفانہ کا سا مزاج کسی کو حق سے دور کرنے کے لیے کافی مدد گار ثابت ہو سکتا ہے ۔
تیسرے خطبہ’’ تاریخ نزول قرآن مجید‘‘ پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کی مکمل تاریخ (history) کو بیان کیا جس میں وحی اول سے لے کر وحی آخر اور سورتوں کی مکی و مدنی ترتیب کے حوالے سے کا فی توجہ طلب نکات ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا، ڈاکٹر صاحب ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
’’عربی زبان کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لسانیات کی تاریخ میں یہ زبان اپنی نوعیت کی منفرد زبان ہے۔ اس کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زبان گذشتہ سولہ سو سال سے بغیر کسی ردوبدل کے آج تک موجود ہے۔ دنیا کی ہر زبان دو تین سو سال بعد تبدیلی کے عمل سے گزرنے لگتی ہے ۔اور پانچ سو سال بعد تو مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔‘‘ (ص:۱۱۵)
محترم ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے تو مکمل طور پر اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ زبان ردوبدل سے آج تک محفوظ ہے۔ اگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا کلام کسی آج کے عربی بولنے والے کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اسے بالکل اسی طرح سمجھ سکتا ہے جیسے بعثت نبوی سے پہلے کا عربی دان اور ا گر آج کی عربی کو ہزار سال پرانے عربی دان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کسی قسم کی نامانوسیت کا شکار نہیں ہونے پائے گا، لیکن عربی زبان کی قدامت صرف سولہ سو سالہ تک محدود نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اول قیام گاہ جنت تھی اور وہاں حضرت آدم کو اسماء کی جو تعلیم دی گئی، وہ عربی زبان میں تھی۔ پھر قرآن کریم میں مختلف انبیا کے حوالے سے جو کلام پیش کیا گیا ہے، خواہ وہ حضرت ابراہیم اور اسمٰعیل علیما السلام کے درمیان مکالمہ ہو یا کسی نبی کی کوئی دعا ،ہو وہ سب عربی زبان میں آج تک من وعن محفوظ ہے بلکہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے الاتقان میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اور صحائف جتنے بھی نازل ہوئے، ان کی اصل زبان عربی تھی۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو ان کی زبان میں ترجمہ کرکے ان کو پہنچایا۔ ان میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی زبان یعنی عربی میں باقی ہے۔ اس بات پر مزید غوروفکر کے لیے صفدر قریشی صاحب کی کتاب ’’وحدت اللسان‘‘ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب کی زبان سے قرآن کے عربی زبان میں نزول کی ایک دوسری حکمت ملاحظہ فرمائیں:
’’ہر زبان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ انگریزی زبان کا ایک مزاج ہے، فرانسیسی، ہندی، سنسکرت وغیرہ زبانوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کسی زبان کا یہ مزاج اس قوم کے عقائد، تصورات، اور خیالات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی زبان کا مزاج ایسا ہے کہ آپ اس میں ایک گھنٹہ بھی بات کر یں اور کوئی صاف بات نہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سننے والا سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔آپ کی بات مثبت ہے، منفی ہے، تائید میں ہے، تردید میں ہے، دوستی ہے، دشمنی ہے کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ یہ حیلہ گری اور شعبدہ بازی صرف انگریزی زبان میں ہی ممکن ہے۔ کسی اور زبان میں ممکن نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ صدر بش کے ساتھ ہیں یا صدر صدام کے؟ اگر آپ اس کا جواب اردو میں دیں تو آپ کو ’ہاں‘ یا ’نہیں‘ میں واضح اور دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا، لیکن انگریزی ایسی زبان ہے کہ آپ اس کے جواب میں ایک گھنٹہ بھی بولیں تو کسی کو پتا بھی نہیں چل سکے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ اس زبان کا خاصہ ہے۔‘‘ (ص:۱۱۵)
سچ تو یہ ہے کہ اگر عربی زبان کی وسعت یا فصاحت و بلاغت کے حوالے سے بات کی جاتی تو واقعی عربی زبان سے کسی اور زبان کا مقابلہ ممکن نہیں، لیکن انگریزی یا کسی بھی زبان کو اس حوالے سے مخصوص کرنا کہ اس میں اپنی اصل بات کو دو ٹوک انداز میں پیش کرنے سے گریز کیا جا سکتا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کیوں کہ ہر زبان میں بشمول عربی کے اس بات کی گنجائش موجود رہتی ہے کہ اپنی اصل رائے کو چھپایا یا اپنی بات کو ملمع سازی سے پیش کیا جا سکے۔ زبان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی فکر میں تضاد پایا جاتا ہے۔ موصوف ایک مقام پر تو(جیسا کہ پچھلی سطروں میں ذکر ہو چکا) قرآن مجید کے انقلاب آفریں اعلان کی بابت فرماتے ہیں کہ قرآن نے غیر اختیاری امور کی بنیادوں پر روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کی نفی کر کے وحدتِ انسانی اور مساوات کی راہ ہموار کی اور اس سلسلے میں ڈاکٹر غازیؒ زبان کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ’’کسی شخص کی مادری زبان کا انتخاب اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا‘‘۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی مادری زبان انگریزی ہے، کیا وہ وحدتِ انسانی کے دائرے میں نہیں سما سکتے؟ کیا ایسے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب کے نشتر کی چبھن محسوس نہیں ہو گی؟ یہاں قرآن مجید کا انقلاب آفریں پیغام کہاں گیا؟ سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر غازیؒ انگریزی زبان سے تعصب برت رہے ہیں، جبکہ وہ بھی دیگر زبانوں کے مانند ایک انسانی زبان ہے۔
ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ ایک اور حکمت ملاحظہ فرمائیں :
’’نزول قرآن کے لیے ایسی زبان کا انتخاب ضروری تھاجو ایک طرف تو مکمل طور پر ترقی یافتہ ہو اور دوسری طرف اس پر کسی غیر اسلامی عقیدے یا تصور کی چھاپ نہ ہو۔ عربی کے علاوہ اس وقت کی تمام زبانوں پر غیر اسلامی عقائد و خیالات کی گہری چھاپ موجود تھی۔ عربی زبان ترقی یافتہ بھی تھی اور ایسی ترقی یافتہ کہ آج تک کوئی زبان اس مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی۔‘‘ (ص:۱۱۵)
یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب کی مراد واضح نہیں ہو پاتی کہ آخر ان کے نزدیک غیر اسلامی تصور یا عقیدے کا معیار کیا ہے۔ بت پرستی جن کا عقیدہ اور فطرت سے بغاوت جس قوم کا شیوہ رہا ہو، اس سے زیادہ غیر اسلامی عقیدہ کی پختگی اور کیا ہو سکتی ہے ؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی ہندوبنیے کے تعصب اور جہالت سے قطع نظر کرکے سنسکرت کو غیر اسلامی چھاپ سے محفوظ زبان خیال کرے۔
ڈاکٹر غازی مرحوم قرآن مجید کے تراجم کا تقابل بائبل سے کرکے مسلمانوں کو جھنجوڑتے ہیں اور ڈاکٹر حمید اللہ ؒ کی کتاب القرآن فی کل لسان کے حوالے سے فرماتے ہیں :
’’ دنیا کی ۲۰۵ زبانوں میں قرآن کے کلی یا جزوی تراجم موجود ہیں ۔۲۰۵یہ وہ تراجم ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے خود دیکھے ۔ صرف ایک اردو زبان میں ۳۰۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ انگریزی میں ۱۵۰ سے زیادہ تراجم موجود ہیں ۔ فارسی اور ترکی میں ۱۰۰ سے زائد، فرانسیسی میں ۵۸۱، جرمن میں ۵۵، لاطینی میں ۵۳ اور بقیہ زبانوں میں درجنوں کے حساب سے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں ترجمے مکمل اور کچھ میں نامکمل ہیں۔ یہ معلومات ہمارے لیے اگرچہ بہت خوش کن ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بائبل کے ۱۸۰۰ زبانوں میں ترجمے موجود ہیں۔ یہ خبر ہم مسلمانوں کو بہت کچھ بتا رہی ہے اور بہت کچھ کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔‘‘ (ص: ۱۱۸، ۱۱۷)
خطبہ چہارم میں جمع وتدوین قرآن اورصحابہ و تابعین کی قرآن کے حوالے سے خدمات اوررسم الخط(نبطی، حمیری، کوفی، نسخ) کی تاریخ اور قرآن میں استعمال نیز قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کن اسباب کو اختیار کیا گیا پر مفصل بحث کی گئی ہے ۔مثال کے طور پر:
’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید اکثرو بیشتر جھلیوں سے بنے ہوئے کاغذ پر، کبھی کبھی باہر سے آئے ہوئے عمدہ اور نفیس کاغذ پر، اور کاغذ کے علاوہ اور چیزو ں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ جو صحابہ کرام کاغذ رکھتے تھے، وہ کا غذ بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور جن کے وسائل کم تھے، وہ رق parchment وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ احادیث میں عُسُب کا ذکر بھی آیا ہے جو عسیب کی جمع ہے۔ یہ بھی لکھنے کے لیے کا غذ نما ایک چیز ہوتی تھی اور کھجور کی چھال خشک کرکے کا غذ کی طرح بنا لی جاتی تھی۔ لخاف کا بھی ذکر ہے جو لخف کی جمع ہے۔ یہ ایک چوڑی اور کشادہ سل نما چیز ہوتی تھی۔ یہ پتھر سے بنائی جاتی تھی۔ اس کی شکل غالباً وہ تھی جیسے آج کل بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے۔ رقاع، رقعۃ کی جمع ہے جس کے لفظی معنی رقعہ کے ہیں جسے اردو میں ہم چٹھی بولتے ہیں۔ یہ کاغذ یا چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کتف کی جمع ہے، یہ اونٹ یا بڑے جانور کے مونڈھے کی ہڈی ہوتی تھی جس کو تختی کی طرح ہموار کر لیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ لکڑی کی بڑی اور کشادہ شاخوں سے بنائی ہوئیں تختیاں یا الواح بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔‘‘ (ص: ۱۲۵)
خطبہ پنجم ’’علم تفسیر: ایک تعارف ‘‘میں فہم قرآن میں تفسیر بالقرآن، تفسیر بالسنۃ اور جاہلی شعری ادب کی اہمیت پر زوردیا گیا ہے۔ خطبہ ششم ’’تاریخ اسلام کے چند عظیم مفسرین قرآن‘‘اور خطبہ ہفتم ’’مفسرین قرآن کے تفسیری مناہج‘‘ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مفسرین قرآن کا تعارف اور ان کی خدمات کا تفصیلی ذکر کیاگیا ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تفسیری خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے صدی کی ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا کہ کس صدی ہجری میں تفسیری کام کی نوعیت کیا تھی اور مفسرین کی دلچسپی کا میدان کیا تھا۔ اس کے علاوہ مفسرین کے اسالیب اور تفاسیر کی خصوصیات کے حوالے سے بھی خوب بات کی گئی ہے۔خطبہ ہشتم ’’اعجاز القرآن‘‘ میں قرآن مجید کے معجزاتی کلام ہونے کے بارے میں مختلف حوالوں سے مدلل اور پرمغز گفتگو کی گئی ہے۔ خطبہ نہم ’’علوم القرآن ایک جائزہ‘‘کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:
’’علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم و معارف ہیں جو علماء کرام مفسرین اور مفکرین ملت نے گذشتہ چودہ سو سال میں قرآن مجید کے حوالے سے مرتب فرمائے۔ ایک اعتبار سے اسلامی علوم و فنون کا پورا ذخیرہ قرآن مجید کی تفسیر سے عبارت ہے۔ آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل مشہور مفسر قرآن اور فقیہ قاضی ابوبکر ابن العربی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے علوم وفنون ہیں، جن کا انہوں نے اس وقت اندازہ سات سو کے قریب لگایا تھا، وہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ سنت رسول کی شرح ہے۔ اس اعتبار سے سارے علوم و فنون علوم القرآن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام سے وابستگی کا بھی یہی تقاضا ہے، وحدت علوم کا منطقی نتیجہ بھی یہی ہے اور وحدت فکر اور تصور وحدت کائنات کا بھی یہی ثمرہ ہے کہ سارے علوم و فنون کو قرآن مجید سے وہی نسبت ہو جو پتوں کو اپنی شاخوں سے، شاخوں کو اپنے تنے سے اور تنے کو اپنی جڑ سے ہوتی ہے۔‘‘ (ص:۲۸۳)
ڈاکٹر غازی صاحب نے علوم القرآن کو دو دائروں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ دائرہ جن کا تعلق براہ راست قرآن کریم کی تفسیر اور فہم سے ہے۔ علوم القرآن کا دوسرا دائرہ ڈاکٹر صاحب نے انسان کی ہر اس فکری کاوش کو قرار دیا جس کی سمت درست اور اساس صحیح ہو۔ علوم القرآن کے پہلے دائرہ کو بیان کرتے ہوئے(جو کہ ڈاکٹر صاحب کا اصل موضوع ہے) فضائل قرآن، خواص القرآن، امثال القرآن، اقسام القرآن، قصص القرآن، حجج القرآن، جدل القرآن(علم مخاصمہ)، غریب القرآن، ناسخ ومنسوخ، مشکلات القرآن وغیرہ مو ضوعات کا تفصیلی تعارف دیا گیا ہے۔علوم القرآن کے دوسرے دائرے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے گذشتہ ساٹھ ستر سال سے اہل فکرو دانش کوشاں ہیں۔ یہ وہ کوشش ہے جسے islamization of knowledge کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتاہے ...... اس دائرے میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے مسلمانوں نے اپنی فکری اور علمی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہو اور جو قرآن مجید کے بتائے ہوئے تصورات کے مطابق ہو اور اس کی بنیادی تعلیم سے ہم آہنگ ہو۔ جب مسلمان اپنے تمام موجودہ معاشرتی اور انسانی علوم کو از سر نو مدون کر لیں گے تو وہ اسی طرح سے قرآن فہمی میں مدد گار ثابت ہوں گے جس طرح ماضی میں مسلمانوں کے معاشرتی اور انسانی علوم نے قرآن فہمی میں مدد دی۔ مسلمانوں کا فلسفہ اور تاریخ اپنے زمانے میں اسلامی نظریہ اور اسلامی تعلیم میں ممدومعاون ثابت ہوا۔جب آج کا اصول قانون، آج کی سیاسیات، آج کی معاشیات، اور آج کے دوسرے تمام علوم اسلامی اساس پر از سر نو مرتب ہوں گے تو اس وقت ایک بار پھر ان سب علوم کی حیثیت قرآن مجید کے خادم اور قرآن فہمی کے آلات وو سائل کی ہوگی۔ اس وقت یہ سب علوم وفنون اسی تصور حیات اور نظریہ کائنات کو فروغ دیں گے جو قرآن مجیدنے دیا ہے۔ اس وقت یہ علوم قرآن مجید کی تہذیبی اقدار کو نمایاں کریں گے اور اس تصور کی بنیاد پر مزید نئے علوم اور فنون کو جنم دیں گے جو قرآن مجید میں ملتا ہے۔‘‘ (ص: ۲۸۴، ۲۸۳)
ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کی پستی ، نا اہلی اور ناکامی کے اسباب کا تجزیہ اس طرح کرتے ہیں:
’’آج مسلمان کے پاس رائج الوقت تمام علوم وفنون اکثر و بیشتر مغربی ذرائع و مصادر سے پہنچے ہیں۔ ان سب علوم کی اساس اور ان سب نظریات کی اٹھان ایک غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ غیر اسلامی نظریات و تصورات اور لا دینی افکا رو اساسات پر ان سارے علوم و فنون کا ارتقاء ہوا۔‘‘( ص:۲۸۳)
خطبہ دہم ’’ نظم قرآن اور اسلوب قرآن‘‘ کے موضوع پر ڈاکٹر غازی صاحب نے نظم قرآنی اور اسلوب قرآنی پرگفتگو کرتے ہوئے اس بات کی حکمتیں ذکر کی ہیں کہ قرآن مجید کو بائبل اوردوسری کتب کی طرح موضوعات کے اعتبار سے کیوں ترتیب نہیں دیا گیا۔ خطبہ یازدہم ’’قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین‘‘ میں ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو دو مختلف انداز میں پیش کیا جس میں پہلے حضرت شاہ ولی اللہ ؒ کے بیان کردہ علوم خمسہ (تذکیر باحکام اللہ، مخاصمہ، تذکیز بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعدالموت) کا مکمل ذکر کیا۔ اس کے بعد اپنے غور وفکر سے اخذ کردہ قرآن مجید کے جن پانچ بنیادی مضامین کا ذکر فرمایا، ان میں عقیدہ، احکام، اخلاق، تزکیہ اور احسان، امم سابقہ کا تذکرہ، موت وما بعد الموت شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ کے حوالے سے باقی مضامین کی نسبت قدرے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے دور جدید میں عقیدہ کی خرابی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایاہے کہ :
’’ دور جدید کے انسان نے ایک شخص کو تو خدا بنانا چھوڑ دیا ہے،البتہ ایک سے زائد افراد پر مشتمل گروہوں اور جماعتوں کو خدائی کا مقام ہمارے اس جدید دور میں بھی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر برطانوی پارلیمنٹ کو لے لیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار مطلق حاصل ہے۔ وہ جو چاہے کرے، سوائے اس کے کہ وہ کسی مرد کو عورت اور کسی عورت کو مرد نہیں بنا سکتی۔ یہ وہ قدرت کاملہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو فرعون کے مقام پر فائز کرنے کے مترادف ہے۔ جس کو وہ جائز سمجھے، وہ جائز اور جسے نا جائز سمجھے، وہ ناجائز ہے۔ جو حیثیت اہل عراق نے نمرود کو اور اہل مصر نے فرعون کو دی تھی، وہ حیثیت اہل انگلستان نے پارلیمنٹ کو دے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلوں نے یہ خدائی حیثیت ایک فرد کو دی تھی اور پچھلوں نے ایک گروہ کو دے رکھی ہے، بعض اوقات گمراہی ایک شخص کی طرف سے آتی ہے تو محدود ہوتی ہے، لیکن اگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گمراہی آئے تو اس کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔‘‘ (ص:۳۶۶)
ڈاکٹر غازی مرحوم کے محاضرات چونکہ مدرسات کی تربیت کے حوالے سے منعقد کیے گئے تھے اس لیے ان میں جہاں جا بجا طریقہ تدریس اور قرآن مجید سے عامۃ المسلمین کی دلی وابستگی کی ممکنات کے حوالے سے بات کی گئی، وہیں فرقہ واریت کے نتائج اور نقصانات سے بھی صرف نظر نہیں برتاگیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دین اسلام کو وحدت کا ضامن قرار دیتے ہوئے ان خامیوں اور رکاوٹوں کا بھی ذکر کیا جو وحدت کی چادر کو چاک کیے ہوئے ہیں۔ اوراس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے (اگر کوئی کرنا چاہے) ملاحظہ فرمائیں:
’’مسلم معاشرے کے بارے میں نظری طور پر تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں دین اور دنیا کی تفریق موجود نہیں ہے۔ اس کی تعلیم میں بنیادی نکتہ توحید اور وحدت ہے۔ نہ صرف دین و دنیا کی وحدت ہے، بلکہ علوم و فنون کی وحدت اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب وتمدن کی اساس ہے۔ اس تعلیم پر کامل ایمان کے علاوہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی امت مسلمہ میں وحدت کی بنیاد ہے۔ دین کی تعلیم کو جتنا فروغ دیا جائے گا، اتنا ہی مسلم معاشرہ میں وحدت فکرونظر پیدا ہوگی۔ نظری اعتبار سے تو سب لوگ یہ بات مانتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عملاً ایسا نہیں ہو رہاہے۔ دینی تعلیم کے بہت سے مراکز ایسے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام پر جو تعلیم آرہی ہے، وہ معاشرے کو مسلکوں اور فرقوں کے نام پر مختلف حصوں میں بانٹ رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ مسلم معاشرہ میں پہلے سے جتنے گروہ یا فرقے موجود تھے، ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے مذہبی تعلیم کا یہ خاص رنگ اور انداز پھیل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں تقسیم اور تفریق میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یا تو آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید اور دین اسلام مسلمانوں میں وحدت کاضامن نہیں جو بالکل بے بنیاد اور خلاف حقیقت بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں ہی کوئی خامی ہے۔ ہم جس انداز سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں جس میں بنیادی زور مسلکی آرا اور فقہی اجتہادات پر دیا جاتا ہے، اس طرز عمل میں بہت کچھ اصلاح اور نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مزید برآں ہمارے ہاں دین کے حوالہ سے جو ذمہ داریاں ہیں، وہ مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان سطحوں کو جب تک اپنی جگہ برقرار نہ رکھا جائے، اس وقت تک اس وہ نتائج برآمد نہیں ہوسکیں گے جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے۔‘‘(ص:۳۸۰)
ہمارے نام نہاد مذہبی فکر رکھنے والے (فکر کم ایکٹنگ زیادہ) طبقے میں اکثریت ان لوگوں کی ملے گی جنہیں اپنے مخصو ص حلقے کے علاوہ سب کچھ باطل ہی دکھتا ہے۔ امت کی پریشانیوں سے صرف نظر کرکے منا ظروں کی محفلیں گرمانا اور چوکوں چراہوں پر روڈ بلاک کرکے ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف پاک بھارت سے بڑا محاذ سمجھ کر ’’جآء الحق وزھق الباطل‘‘ کے نعرہ لگانا جن کا شیوہ اور ایک دوسرے کے مسلک کے اکابر پر انگلی اٹھانا جن کا شعار ہو، آخر ایسے لوگوں کاخود کو ناجی فرقہ قرار دینے اور فرقہ ثانی کو جہنم کا مستحق سمجھنے کے علاوہ اور مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ تمام اکابرین دین کا احترام کرنے والے ایک سنجیدہ آدمی کے لیے اس سے بڑا تکلیف دہ امراور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا داؤد غزنوی پر سب و شتم ہوتے سنتا ہے اور دوسرے دن اسی مقام پر سیدحسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد رضا خاں بریلوی پر انگلیاں اٹھتے دیکھتا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے استاد محترم مولانا زاہد الراشد ی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مدرسہ نصرۃ العلوم میں دورۂ حدیث کے طلبہ کوجمعرات کے دن مختلف موضوعات (تعارف ادیان ،تعارف مذاہب ، تعارف مسالک اور بین الاقوامی تعلقات) کے حوالے سے لیکچرز دیا کرتے ہیں۔ اس دوران جب تعارف مسالک پر بات کرتے ہیں تو استاد محترم جس طریقہ سے علماے دیوبند کا تعارف کرواتے ہیں، اسی طریقہ سے علماے اہل لحدیث اور بریلوی علما کا نہ صرف تعارف کراتے ہیں بلکہ ہر مسلک کے عالم کی خصوصیات کا بھی ذکر فرماتے ہیں جس سے اس عالم کی قدر اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسے ہی علما کی راہ نمائی کا محتاج ہے تا کہ وحدت کی کھوئی ہوئی متاع کوہم دوبارہ حاصل کر پائیں۔لیکن افسوس! صد افسوس ایسے علما اتنی کم تعداد میں ہیں کہ بآسانی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے بھی فرقہ پرست علما کی کثرت دیکھتے ہوئے ان کے ضمیر کو جھنجوڑنے کی( ناکام) کوشش کی تھی:
منفعت ایک ہے اس قوم کی ، نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں!
بہرحال! ڈاکٹر غازی مرحوم نہ صرف قرآن سے رابطہ استوار کرنے کی بات کرتے ہیں بلکہ ہر عالم کے اظہار رائے کے حق کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور دروس قرآن کی محافل میں پائے جانے والے دوہرے معیار پر بھی کڑی تنقیدفرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:
’’ہمیں درس قرآن کے حلقے منظم کرنے ہیں۔ یعنی لوگوں کو دین کے بنیادی عقائد پر جمع کرنا اور شریعت کی تعلیم اس طرح دیناکہ جہاں جہاں خود شارع نے اختلاف کی گنجائش رکھی ہے اس اختلاف کو آپ تسلیم کریں۔ اب ہوتا یہ ہے جو بالکل درست نہیں ہے کہ ایک عالم کا درس قرآن ہوتا ہے، اس میں صرف اس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جو ان عالم کا اپنا فقہی یا کلامی مسلک ہوتا ہے۔ دوسرے مسلک کا کوئی آدمی حاضرین اور سامعین میں موجود نہیں ہوتا۔ترجمہ قرآن بھی اپنے مسلک کے عالم کا مخصوص ہوتا ہے۔ یوں تو کسی ترجمہ یا تفسیر کو مخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے بہتر اور مناسب یہی ہے جس سے آپ کا ذوق ملے اسی عالم کے ترجمہ اور تفسیر کو آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کریہ کہا جائے کہ فلاں ترجمہ اور تفسیر ہی کو پڑھا جائے، اس کے علاوہ کسی اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ پڑھا جائے تو یہ بات غلط ہوگی۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کو زبردستی اپنے ذوق پر جمع کرے۔‘‘(ص:۳۹۱)
اگر ہندو اور عیسائی مذہب کے پیروکارجہالت کی وجہ سے اپنے پنڈت اور پادری کو پا ک صاف اور ہر غلطی سے منزہ سمجھتے ہیں تو خیر سے ہمارے ’’مذہب شناس‘‘ لوگ بھی اپنے اکابرین کو پوجنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے ۔ اسی رویہ پر ڈاکٹر غازیؒ بڑے اچھے انداز میں تنقید فرماتے ہیں ۔ملاحظہ فرمائیں:
’’اگر غلطی ابوبکرصدیقؓ سے ہو سکتی ہے تو پھر کوئی شخص بھی غلطی سے مبرا نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ سے فہم قرآن سے چوک ہوتی ہے اور وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ سے غلطی ہوگئی، ہمارے لیے یہ کہہ دینا بھی بہت سہل ہے کہ امام شافعی نے فلاں جگہ غلطی کی اور یہ کہہ دینا بھی آسان ہے کہ امام مالک نے فلاں بات صحیح نہیں سمجھی۔ ہماری دینی درس گاہوں میں روز یہ تنقیدی تبصرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہنے کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ مولانا تھانوی یا مولانا مودودی یا مولانا احمد رضاخان سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ کوئی ذرا یہ جرات کرکے دیکھے! ان کے مریدین سر توڑ دیں گے اور اسلام سے خارج کرکے دم لیں گے۔‘‘ (ص: ۴۰۱)
ہم اپنے مضمون کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر ڈاکٹر غازی مرحوم کے کام اور ان کی لگن کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اتنے مشکل مضامین کو انہوں نے سلاست کا جامہ پہنایا تاکہ ایک عام اردودان بھی ان سے استفادہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ غازی مرحوم کی اس محنت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے علمی ذخیرہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ڈاکٹر غازیؒ اور ان کے محاضرات قرآن
سید علی محی الدین
غازی صاحب کی رحلت کا حادثہ ایسا اچانک ہوا کہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہم میں نہیں رہے۔ نہ جانے ہم جیسے کتنے طالب علموں نے ان سے استفادے اور رہنمائی کے کیسے کیسے منصوبے بنا کر رکھے تھے، مگر وہ اپنے حصے کا کام انتہائی تیز رفتاری سے نمٹا کر لوگوں کو اداس اور دل گرفتہ چھوڑتے ہوئے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس عالم کو سدھار گئے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔
ڈاکٹر غازی صاحب کو جاننے، سمجھنے اور قریب سے ان کی شخصیت کا مطالعہ کرنے والے آج یقیناًاداس ہیں۔ یہ غم اس بنا پر نہیں کہ ایک استاد، قانون فہم، جدید وقدیم کی جامع، علوم اسلامیہ پر محققانہ نگاہ رکھنے والی، عربی زبان وادب کی ماہر، متوازن ومعتدل اور تعلیمی امور کو سمجھنے والی شخصیت رخصت ہوئی، بلکہ ان تمام کمالات اور خوبیوں کے ساتھ وہ کردار، اخلاق، سیرت، قلبی اور باطنی حالات کے لحاظ سے بھی ان شخصیات میں سے تھے جن کی تعداد محدود تر ہے۔ ہم القابات اور اعزازات عطا کرنے میں نہایت فراخ دل اور سخی واقع ہوئے ہیں۔ راہ چلتے معمولی کارناموں کے حامل افراد کووہ بلندوبالا القابات عطا کر دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ غازی صاحب کے سلسلے میں جو لقب اور اعزاز طویل غوروخوض کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ ’’علم دوست شخصیت‘‘ کا ہے جس کا اوڑھنابچھونا اور دلچسپیوں، مہارتوں اور صلاحیتوں کامرکز ومحور علم ہی تھا۔
ڈاکٹر صاحب کی خدمات وخصوصیات ایسی نہیں جنہیں عجلت میں بلاغوروخوض سپردقلم کر د یا جائے۔ ان کے فکری، ذہنی، علمی کمالات بڑا تدبر چاہتے ہیں۔ فوری طور پر حتمی انداز سے طے کرنا کہ وہ عمر بھر کس چیز کے لیے کوشاں رہے، آسان نہیں۔ بسا اوقات خود کام کرنے والی شخصیت کو بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس کا اصل میدان اور دائرہ کیا ہے! اکثرو بیشتر برسوں نہیں، صدیوں پردہ پڑا رہتا ہے۔ عرصہ دراز کے بعد کوئی شخص آکر بتاتا ہے کہ فلاں صدی میں گزرنے والی شخصیت کا اصل کارنامہ کیا تھا۔ اس خیال اور مضمون کو مولانا سید ابوالحسن ندویؒ نے ’’تاریخ دعوت وعزیمت‘‘ میں خوب سمجھایا ہے۔ اصلاً تو اس کتاب میں اصلاح وتجدید کی اسلامی تاریخ میں جو تسلسل ہے، اس کو حضرت ندویؒ نے دکھایا ہے، لیکن ضمناً اس خیال پر بے شمار اشارے ملتے ہیں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ رخصت ہو جانے والی شخصیت کی خدمات وخصوصیات کو سامنے لانے میں کچھ بے اعتدالی اور مبالغہ آرائی کے ساتھ کچھ مسلمہ اصولوں کو بھی بری طرح پامال کیا جاتا ہے۔ اتفاقی جملوں اور واقعات کو بنیاد بناکر پوری شخصیت کو بدل دیاجاتا ہے۔ اپنے خیالات کاخول چڑھا کر دوسروں کے افکار کو بیان کیا جاتا ہے اور صوفی کو ملا، متکلم کو مفسر اور محدود قسم کی شخصیات کوعالمی بنا دیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ مبالغہ آرائی اور عقیدت کے تحت سرانجام دیا جاتا ہے۔ اقبال کی مثال سب سے زیادہ واضح ہے۔ اسلامی شریعت کے مداحین اور ناقدین بیک وقت اقبال سے یوں فائدہ اٹھاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ اقبال کی جامعیت ہے یا استدلال کرنے والوں کی تحریف۔
خیر، بات دور نکل گئی۔ غازی صاحب کے کام کا مختصر سا خاکہ ان کے سلسلہ محاضرات کی روشنی میں سامنے لانے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کی خدمات کے صرف ایک پہلو کا، جو علوم اسلامیہ کے میدان میں ظاہرہوا، کچھ ہلکا سا اندازہ ہو جائے۔ ان خطبات کے بعض طویل اقتباسات بھی نقل ہوں گے تاکہ مراد اور منشا واضح ہو سکے۔ ان میں سے کچھ محاضرات براہ راست سننے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔
توسیعی خطبات کے ذریعے علم ومعلومات دینا علمی دنیا میں معروف ومقبول طریقہ ہے اور یہ کئی لحاظ سے اپنے اندر افادیت بھی رکھتا ہے کہ مختصرو قت میں محاضر اپنی زندگی بھر کا مطالعہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ روایت برصغیر میں بھی کسی حد تک موجود ہے، اگرچہ کم یاب ہے۔ علامہ اقبال کے مشہور خطبات، مولانا سید سلیمان ندویؒ کے خطبات مدراس، ڈاکٹر حمیداللہ کے خطبات بہاولپور، مولانا سیدا بوالحسن ندویؒ کی ’’ النبوۃ والانبیاء فی ضوء القرآن‘‘ (منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین) اور برصغیر سے باہر ڈاکٹر فواد سیزگین کی ’’التراث العربی‘‘ اس کا معیاری نمونہ ہیں۔ غازی صاحب کے ان خطبات کا آغاز ۲۰۰۳ء میں محاضرات قرآنی سے ہوا اور تکمیل ۲۰۰۹ء میں محاضرات معیشت وتجارت پر ہوئی۔اس لحاظ سے کل۶سال کے عرصے میں محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت، محاضرات فقہ، محاضرات شریعت اور محاضرات معیشت وتجارت منصہ شہود پر آئیں۔
میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ ۶سال کے مختصر عرصے میں یہ خطبات ان سے دلوائے گئے اور جب اس کی تکمیل ہوئی تو بلاوابھی آگیا۔ ان خطبات کی محرک اول ان کی بہن تھی جو درس قرآن کے عمل سے وابستہ تھیں۔ انھیں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ خالی الذہن عوام الناس کو اسلامی علوم سے روشناس کروایا جائے، لیکن ان محاضرات سے استفادہ اہل علم نے بھی بڑے پیمانے پر کیا۔ ان خطبات میں مذکورہ بالا تمام علوم کے مختلف مضامین ومباحث، اساسی تصورات اور ضروری پہلوؤں کو جس آسان، عام فہم، دل نشین، متوازن او رمعتدل انداز میں بیان کیا گیا ہے، وہ ان کی زندگی بھر کی خدمات میں ایک نمایاں مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ خالص خشک اور علمی موضوعات ومباحث میں دلچسپی وجاذبیت پیدا کرنا آسان نہیں۔ مغلق، پیچیدہ اور دقیق فنی اصطلاحات کو روز مرہ کی زبان اور مثالوں سے ذہن نشین کرانا ایک مشکل کام ہے۔
ان محاضرات کو پڑھ کر اسلامی علوم کی وسعت، گہرائی اور جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے شاندار علمی ماضی، قدیم ورثہ اور اسلاف کے کارناموں پر اعتماد اور اطمینان بڑھتا ہے۔ ایک نہایت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قدر وسیع علم رکھنے والی شخصیت اپنی ذاتی رائے اور خیال ظاہر کرنے میں حد درجہ احتراز سے کام لیتی ہے۔ آج کے زمانے میں جن حضرات کی نظر کچھ وسیع ہو جاتی ہے، وہ مسلمات اور علوم وفنون کی نمائندہ شخصیات سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے عدم اعتماد اور حقارت کا رویہ اپنانے لگتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ خصوصیت بھی قابل غور ہے کہ اپنے آپ کو ان اسلاف کا ناقل قرار دینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کی گفتگو واضح، دو ٹوک، ابہام اور الجھاؤ سے پاک، توازن واعتدال، وسعت وجامعیت اور سلیقہ وادب کا نمونہ، سلف پر مکمل اعتماد کی مظہر اور حکمت ودانش سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ مستشرقین اور سرسید احمد خان کی مثبت علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ عظیم ترین مفسرین اور محدثین، جن کے حوالے سے ہم مسلکی تعصبات کا شکار ہیں، حکمت کے ساتھ سب کے مطالعہ کی ترغیب اور شوق دلاتے ہیں۔ عقائد اور اعمال کی اصلاح کا حکیمانہ اسلوب وطریقہ متعارف کرواتے ہیں۔ جم کر علمی کام نہ کرنے کے مزاج کا شکوہ کرتے ہیں۔
وہ نفاذ شریعت کے سلسلے میں عملی مشکلات اور رکاوٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ مشکلات دستوری اور آئینی ہیں، کچھ کا تعلق ہماری سہل پسندی اور راحت طلبی سے ہے، بعض علم ومہارت کے فقدان سے تعلق رکھتی ہیں، فہم وبصیرت کی کمی بھی موانع میں سے ہے اور کچھ کا عمومی تربیت اور اصلاح کے ساتھ واسطہ ہے۔ ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کا حل تلاش کیے بغیر محض نفاذ شریعت کا نعرہ لگانا عجیب تر ہے۔ ریاست اور اس کے مرکزی اداروں کی اہمیت کا شعور اور نظام کو اسلامی بنانے میں کہاں بیٹھ کر موثر اور مفید کام کیا جا سکتا ہے، یہ چیز نہایت بالغ نظری چاہتی ہے۔ وہ سیاسی وتحریکی شعور بھی رکھتے ہیں۔ سیاست علم وآگاہی کے ساتھ چلتی ہے اور مفید علمی اور قانونی کام کے لیے سیاسی شعور حد درجہ ناگزیر ہے۔ مفکرین کی غلطیوں کی سزا نسلیں اور جماعتیں بھگتتیہیں۔
علوم کے میدان میں متعلقہ علم کی تاریخ، آغاز، نمائندہ شخصیات، امہات کتب اور برصغیر میں اس علم کی خدمت کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ علم کب اور کہاں پیدا ہوا؟ نوک پلک کہاں سنواری گئی؟ عروج کب ملا؟ شرح وتحشیہ کب شروع ہوئی؟ گھن کب لگا؟ برصغیر اور مستقبل میں اس علم کی وسعت کے کیا امکانات ہیں؟ یہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ نمونے کے طور پر محاضرات قرآنی سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔
برصغیر اور موجودہ پاکستان میں عوامی سطح پر درس قرآن کی تاریخ کیا ہے اور اس مبارک سلسلے کے آغاز کا احساس سب سے پہلے کن حضرات کو ہوا؟ اس ضمن میں فرماتے ہیں:
’’ہمارے موجودہ پاکستان کے علاقوں میں بیسویں صدی کے اوائل میں بعض بزرگوں نے اس کام کو ازسر نو شروع کیا جن میں بڑا نمایاں نام حضرت مولانا عبیداللہ سندھیؒ اور ان کے نامور شاگرد مولانا احمدعلی لاہوری کا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری نے سب سے پہلے لاہور میں ۱۹۲۵ء کے لگ بھگ عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا جو تقریباً چالیس پینتالیس سال تک، جب تک مولانا زندہ رہے، جاری رہا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ پاکستان میں چپے چپے میں درس قرآن کی محفلیں جاری ہیں اور مختلف سطحوں اور مختلف انداز سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص قرآن مجید کے پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے۔‘‘ (ص ۲۸)
عوامی اور عمومی سطح پر تدریس قرآن میں مخاطبین کی ذہنی وعلمی سطح کی رعایت واحترام از حد ضروری ہے۔ سب کو یکساں غذا اور مواد دینا اور مشترکہ اسلوب میں گفتگو کرنا موثر اور مفید نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:
’’درس قرآن کے اسلوب اور منہاج پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرورخیال رکھنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے درس کے مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین کا لحاظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مخاطبین کی بہت سی علمی اور فکری سطحیں ہوتی ہیں۔ بہت سے پس منظر ہوتے ہیں اور ان سب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات درس قرآن کا مخاطب ایک عام تعلیم یافتہ شہری ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے اور ضروریات اور ہوتے ہیں۔ اگر درس قرآن کا مخاطب کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے تو اس کے تقاضے اور معیار اور ہوگا اور اگر فنی تعلیم کے متخصص لوگ آپ کے درس کے مخاطب ہیں، مثال کے طور پر ایک قانون کا متخصص ہے، ایک فلسفہ کا متخصص ہے تو ایسے لوگوں کے تقاضے اور ہوں گے، لیکن اگر آپ کے درس کے مخاطبین قرآن مجید کے متخصصین، مثلاً درس نظامی کے طلبہ یاعلماء کرام ہیں تو ان کی ضروریات اور تقاضے اور ہوں گے۔ اس لیے پہلے یہ تعین کر لینا چاہیے کہ ہمارا ہدف کیا ہے اور ہم کس طبقے کو خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ جس طبقے اور جس معیار کے لوگوں سے بات کرنی ہو، اس طبقے کے فکری پس منظر، اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات، اس طبقے میں اٹھائے جانے والے سوالات اور ان شبہات اور سوالات کا منشا پہلے سے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔‘‘ (ص: ۲۹)
نزول قرآن کے مقاصد واہداف کیا ہیں؟ شاہ ولی اللہ ؒ نے تین مقاصد بیان کیے ہیں: اخلاق، عقیدے اور عمل کی اصلاح۔ شاہ صاحب کے مقاصد ثلاثہ کی تشریح میں عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے جو حکمت اور دانش درکار ہے، اس پر یوں روشنی ڈالتے ہیں:
’’دوسری چیز جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے، وہ ہے دمغ العقائد الباطلۃ یعنی وہ تمام باطل عقائد جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، خواہ مسلمانوں کے ذہن میں ہوں یا غیر مسلموں کے، ان سب باطل عقائد کی تردید کی جائے۔ بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے مخاطب کے ذہن میں ہوتاہے اور اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں انگڑائیاں لیتا رہتا ہے، لیکن وہ غلط خیال اس کے ذہن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ خیال کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرسکے، اس لیے وہ خود تو اس سوال کو پیش نہیں کرے گا۔ اگر آپ از خود اس کی تردید نہیں کریں گے تو وہ سوال اس کے دماغ کے گوشوں میں کلبلاتا رہے گا اور الجھن اس کے ذہن میں قائم رہے گی۔ آپ کے درس قرآن کے باوجود اس کی وہ الجھن صاف نہیں ہو گی۔ اس لیے آپ پہلے سے اس کا اندازہ اور احساس کر لیں کہ مخاطب کے ذہن میں کیا کیا شبہات آ سکتے ہیں اور اپنے درس میں اس شبہے اوراعتراض کا تذکرہ کیے بغیر اور یہ کہے بغیر کہ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا شبہ موجود ہے، وہ از خود اس شبہے اور اعتراض کا جواب ایسے انداز سے دے کہ وہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ جو قرآن مجید کی رو سے غلط عقیدہ ہے او ر ایک خیال جو قرآن مجید کی روسے غلط خیال ہے اور ایک تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ غلط تصور ہے، لیکن کسی وجہ سے اس غلط عقیدہ، غلط خیال یا غلط تصور کے حق میں اس کے ماننے والوں میں کوئی عصبیت بھی پیدا ہوگئی اور اس عصبیت کا کوئی خاص پس منظر ہے تو ایسی صورت حال میں مناسب یہ ہے کہ عمومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقف کی تشریح وتفسیر اس انداز سے کی جائے کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ اگر آپ نام لے کر تردید کریں گے کہ فلاں شخص یا فلاں گروہ کے لوگوں میں یہ خیال یا یہ چیز غلط ہے تو اس سے ایک رد عمل پیدا ہوگا اور ایسا تعصب پیدا ہو جائے گا جو حق کو قبول کرنے میں مانع ہو گا۔
تعصب سے ضد پیدا ہوتی ہے۔ ضدبالآخر عناد کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔ پھر انسان کے لیے حق بات قبول کر لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت حال میں انسان کا نفس اس کے غلط خیال کو نئے نئے انداز میں سامنے لانا شروع کر دیتا ہے۔ اس اعتراض کا ذکر کیے بغیر اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو پھر تعصب کی دیوار سامنے نہیں آتی۔ قرآن مجید کا یہی اصول ہے۔ قرآن میں اکثروبیشتر سوال کا ذکر کیے بغیر او ر اعتراض کو دہرائے بغیر اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن خود بخود صاف ہو جاتا ہے اورمعترض کے ذہن کی کجی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔
شاہ صاحب کی زبان میں قرآن کا تیسرا مقصد نفی الاعمال الفاسدہ ہے یعنی جو اعمال فاسدہ انسانوں میں رائج ہیں، چاہے ان کی بنیاد کسی غلط عقیدے پر ہو یا نہ ہو، ان اعمال کی غلطی کو واضح کیا جائے اور ان کو مٹانے اور درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط رواج انسانوں میں رائج ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ قرآن مجید کا علم رکھنے کے باوجود یہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کا یہ رواج قرآن مجید کے احکام کے منافی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہیں کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آتا۔ اب اگر آپ نے بطور مدرس قرآن درس کے پہلے ہی دن لٹھ مارنے کے انداز میں یہ کہہ دیا کہ اے فلاں فلاں لوگو! تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو اور اے فلاں فلاں لوگو! تم بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو اور تم ایسے ہو اورایسے ہو تواس سے نہ صرف ایک شدید ردعمل پیدا ہوگا بلکہ اس کے امکانات بہت کمزور ہو جائیں گے کہ آپ کا مخاطب آپ کے پیغام سے کوئی مثبت اثر لے۔ اس انداز بیاں سے مضبوط گروہ بندیاں تو جنم لے سکتی ہیں، کوئی مثبت نتیجہ نکالنا دشوار ہے۔ اس طرز گفتگو سے آپ کے اور مخاطب کے درمیان تعصب کی ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کی تعلیم بیان کرنے پر اکتفا کریں کہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے اور اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں فلاں قسم کے کام نہ کیے جائیں تو اگر فوری طور پر نہیں تو ایک نہ ایک دن قرآن مجید کا طالب علم آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہے اور قرآن مجید کے مطابق آہستہ آہستہ اس کے غلط طور طریقے اور فاسد عمل درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔‘‘ (ص:۲۹۔۳۴)
مغربیت اور اس کے زیر اثر پھیلنے والے افکار سے بچاؤ اور تحفظ محض مواعظ اور تقریروں سے ممکن نہیں، جب تک قرآن کی روشنی میں متبادل اسلامی فکروجود میں نہیں آتا اور اس پر ذہنوں کومطمئن نہیں کیا جاتا۔ موجودہ زمانے میں درس قرآن کے ذریعے ایک بڑا مقصد یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا ارشاد ہے:
’’سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ایسے فکری اور تعلیمی ماحول میں جی رہے ہیں جس پر مغربی افکار، تمدن اور ثقافت کا حملہ روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کے خیالات اور طرز معاشرت پر مغرب کی اتنی گہری چھاپ پڑ چکی ہے کہ درس قرآن میں اس کا نوٹس نہ لینا حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔ مغربی افکار کا اتنا گہرا اثر مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں پر چھا گیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے اسلام کے عقائد اور تعلیمات میں جو چیز بالکل بدیہی ہونی چاہیے تھی، وہ اب بدیہی نہیں رہی، بلکہ محض ایک نظری اور خیالی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی ناپید نہیں ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد اور احکام میں سے بہت سے پہلو نظری سے بھی بڑھ کر ایک مشکوک چیز بن گئے ہیں۔ نعوذباللہ۔
اس لیے جب بھی کبھی دینی ذہن کی تشکیل کا سوال پیدا ہوگا تو یہ بات ناگزیر ہو گی کہ عقیدہ اور فکرکی اس کمزوری اور انحلال کو پیش نظر رکھا جائے۔ آج مغربی افکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے مغرب کے منفی اثرات کو دھونا اور اس کے دھبوں کو مٹا کر صاف کرناا ور وہ قلب وبصیرت پیداکرنا جو قرآن مجیدکا مقصود ہے، ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر ہم سب کے سامنے ہے۔ افسوس کہ اس وقت کہیں بھی کوئی مثالی اسلامی معاشرہ نہیں۔ اس وقت ہم کسی مثالی مسلم معاشرے میں نہیں رہتے۔ ہمارا معاشرہ بعض اعتبار سے مسلم معاشرہ نہیں رہا۔ اگرچہ بعض اعتبار سے یہ اب ایک مسلم معاشرہ ہے، لیکن بعض اعتبار سے ہمارے اس معاشرے میں بہت سی خامیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ غیر اسلامی قوتوں نے ہمارے معاشرے،ہماری ثقافتی زندگی، حتیٰ کہ ہماری عائلی زندگی میں اس طرح مداخلت کر لی ہے کہ جگہ جگہ نہ صرف بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں بلکہ کئی جگہ فکری، ثقافتی او ر تمدنی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس خلا کو پر کرنااور ایک مکمل، متکامل اور متناسق اسلامی نقطہ نظر کی تشکیل کرنا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ مغربی افکار اور نظریات کے منفی حملے کا سد باب صرف اسی وقت کیا جا سکے گا جب ایک مکمل، متکامل اسلامی متبادل پیش کر دیا جائے گا۔ متبادل اسلامی فکر کی عدم موجودگی میں محض مواعظ اور تقریروں سے اس سیلاب کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔‘‘ (ص: ۳۶)
انبیاء کرام کی صحبت اور وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ایسا قطعی، یقینی اور رگ وپے میں اترنے والا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا استدلالی علم اس کو متاثر اور متزلزل نہیں کر سکتا۔ بقول مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ ،امام غزالیؒ کے ذہن میں یہی الجھن اورتشکیک پیدا ہوئی جس نے انہیں بے چین اور مضطرب کردیا اور وہ اس وقت کی سب سے بڑی علمی مسند مدرسہ نظامیہ کی صدارت چھوڑ بیٹھے کہ جو اطمینان اور یقین مجھے اپنے مذہب کی حقانیت اور صداقت پر استدلالی علم کے ذریعے حاصل ہے، وہ ایک یہودی اور عیسائی کو بھی اپنے مذہب کے سلسلے میں حاصل ہے۔ مجھ میں اطمینان اور یقین کی وہ کیفیت جو دو اور دو چار کی طرح ہو، کیوں موجود نہیں کہ اگر کوئی اس کے برعکس استدلال سے ثابت بھی کرے، تب بھی میں اس کو حیرت انگیز واقعے پر محمول کرتے ہوئے اپنے یقین کو قائم رکھوں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے تذکرے میں مولانا ندویؒ نے اس بارے میں گہری تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہی وہ بے چینی تھی جس نے امام غزالیؒ کو امامت کے رتبے پر فائز کر دیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں استدلال اور صحبت کے ذریعے حاصل ہونے والے اطمینان ویقین میں فرق:
’’ انبیاء کرام ؑ کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والوں کے قلب ونظر میں اور رگ وپے اور روح وذہن میں ایسا قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کو پھر کسی ظاہری استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک چھوٹی مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عقلی دلائل اور منطقی استدلال کی بنیاد پر جو چیزیں آج ثابت ہوتی ہیں، وہ کل غلط ہو جاتی ہیں۔ ہر ذہین آدمی جو مناظرہ اور لفاظی کے فن سے واقفیت رکھتا ہو، وہ جس چیز کو چاہے دلائل او ر ز بان آوری کے زور سے صحیح یا غلط ثابت کر سکتا ہے۔ سرسید احمد خان کے صاحبزادے سیدمحمود کے بارے میں آپ نے سنا ہو گا کہ وہ اپنے زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنی مصروفیات اور بعض مشاغل کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی عدالت میں کسی فریق مقدمہ کی طرف سے پیش ہوئے اور بھول چوک کی عادت کی وجہ سے یہ بھول گئے کہ کون سے فریق کے وکیل ہیں۔ انھوں نے مخالف کی طرف سے دلائل دینے شروع کر دیے اور مسلسل دیتے رہے، یہاں تک کہ دلائل کا انبار لگا دیا۔ جس فریق نے انہیں اپنا وکیل مقرر کیا تھا، وہ گھبرا گیا، لیکن کچھ کہنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ بہت بڑے وکیل تھے۔ جب ان کے موکلین بے حد پریشان ہوئے تو انہوں نے خاموشی سے کسی کے ذریعے کہلوایا کہ آپ تو ہمارے وکیل ہیں۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا! پھر عدالت سے مخاطب ہو کر بولے کہ جناب والا! فریق مخالف کے حق میں بس یہاں تک کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب غلط اور بے بنیاد ہے۔ پھر دوسری طرف سے دلائل دے کر اس سارے سلسلہ گفتگو اور استدلال کی تردید کر دی جو وہ اب تک کہہ رہے تھے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دنیا عش عش کر اٹھی۔ تودلائل کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ آپ اپنے زور بیان، قوت استدلال اور زبان آوری سے کام لے کر جس چیز کو چاہیں، سچا اور صحیح اور جس چیز کو چاہیں، جھوٹا اور غلط ثابت کردیں۔
اے کے بروہی ملک کے مشہور قانون دان تھے اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بانی بھی تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا وکیل کون دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا وکیل اور قانون دان سہروردی صاحب کو دیکھا ہے۔ وہ بہت ماہر وکیل تھے۔ جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جس نقطہ نظر کی وہ تائید کر رہے ہیں، ہر چیز اس کی تائید کر رہی ہے۔ زمین وآسمان، درودیوار اور کمرۂ عدالت، کرسی، میز، غرض ہر چیز ان کی تائید کر تی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ اس طرح سماں باندھ دیتے تھے کہ جس چیز کو چاہتے، صحیح ثابت کر دیاکرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی ذاتی دلچسپی تو ہوتی نہیں تھی۔ جو فریق پیسے دیتا تھا، ا س کے حق میں دلائل بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو عقل اور استدلالی دلائل تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ دلائل دینے والا جب چاہے، جس چیز کو چاہے، غلط ثابت کر دے۔‘‘ (ص: ۶۰)
خامی، کمزوری، عیب اور گمراہی کی اصلاح کیسے ہو؟ بسا اوقات ہمارا رد عمل اور گمراہی سے نمٹنے کا انداز واسلوب مزید شدت اور پختگی کا باعث بن جاتاہے۔ مکاتب فکر اور فرقوں کے وجود میں آنے کی تاریخ اگر سامنے ہو تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ معمولی غلط فہمی پر سخت اور غیر حکیمانہ رد عمل نے اگلی نسلوں میں کیسی عصبیت اور پختگی پیدا کر دی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستقل فرقے بنتے چلے گئے۔ غلطی اورگمراہی کو اس کی مقدار میں محدود رکھا جانا چاہیے۔ اصول کو فروع اور فروع کو اصول نہیں بنانا چاہیے۔ غازی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ لوگ دہریت کے مرض میں مبتلا ہیں، تبلیغ کیسے کی جائے؟ جوا ب ملاحظہ ہو:
’’پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دہریت کے فتنے میں گرفتار ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس فتنے میں کیوں مبتلا ہوا اور وہ کون سے اسباب اور محرکات تھے جو اس فتنہ کا ذریعہ بنے۔ سبب معلوم کرنے کے بعد علاج آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی چیز کی ظاہری چمک اور چکاچوند سے بہت جلدمتاثر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پرامریکہ، یورپ گئے۔ وہاں کا ظاہری حسن دیکھ کر بعض لوگ بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہر چیز اچھی اور اپنی ہر چیز بری لگتی ہے، لیکن چند سال بعد خود بخود عقل ٹھکانے آجاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چند مغربی افکار اور تصورات کامطالعہ کرنے کے بعد ایک ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس پہلو سے غلط فہمی ہوئی ہو، اسی پہلو سے اسے دور بھی کیا جائے، لیکن جدید تعلیم یافتہ نوجوان لوگوں کو اسلام سے متاثر کرنے کا بہترین اور سب سے موثر طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کارناموں سے متعارف کروایا جائے جو اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے سائنس، تہذیب، تمدن اور علوم وفنون کے میدان میں انجام دیے۔ اس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ مغربی افکار اور ثقافت کی چمک بہت گہری ہوتی ہے او را س کے مقابلے میں اپنے ورثہ اور تاریخ کی واقفیت نہیں ہوتی۔ اس عدم واقفیت کی وجہ سے اپنے ورثہ پر اعتماد نہیں ہوتا اور اس عدم اعتماد کی وجہ سے اپنے مستقبل سے مایوسی طاری رہتی ہے۔ دوسروں کے ورثہ سے خوب آگاہی رہتی ہے، اس لیے اعتماد بھی انھی کے مستقبل سے وابستہ رہنے پر ہوتا ہے۔ آپ ایک بچے سے شیکسپیئر کے بارے میں پوچھیں تو وہ خوب بتائے گا، شاید اس کے بہت سے اشعار بھی سنا دے، لیکن ذرا اس سے مولانا رومؒ کے بارے میں دریافت کر کے دیکھیں تو شاید اس نے نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ میں ایک صاحب سے ملا ہوں۔ اسپینی مسلمان ہیں، نو مسلم ہیں اور اسلام کے بہت پر جوش مبلغ ہیں۔ ان کے اثرو رسوخ سے تقریباً بیس بائیس ہزار اسپینی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کا اسلام سے واسطہ ا س طرح ہوا کہ ان سے اسپینی حکومت نے کہا کہ ۱۴۹۲ء میں اسپین میں مسلمانوں کو زوال ہوا تھا، اس لیے ۱۹۹۲ء میں مسلمانوں کے زوال کاپانچ سو سالہ جشن منایا جائے اور اس بات کی خوشی منانے کا اہتمام کیا جائے کہ مسلمان یہاں سے پانچ سو سال قبل نکالے گئے تھے۔ ان صاحب سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں آپ ایک کتاب مرتب کر یں جس میں اس دور کے مسلمانوں کے مظالم اور ناانصافیوں کا تذکرہ ہو۔ جب انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو انہیں محسوس ہو اکہ عربی زبان سیکھے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے عربی زبان سیکھ لی اور مسلمانوں کی تاریخ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کے دوران میں وہ اپنے ذاتی مطالعات سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسپین کی تاریخ کا سنہری اور زریں دور وہ تھا جب مسلمان یہاں حاکم تھے۔ علوم وفنون کا چرچاہوا، ادارے بنے، بہترین عمارتیں تعمیرہوئیں، مفید کتابی لکھی گئیں۔ نہ مسلمانوں سے پہلے اس قدر کام ہوا تھا اور نہ مسلمانوں کے بعد ہوا۔ یوں انہیں اسلام سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کے کارنامے جاننے کاموقع ملااور اس طرح اسلام پر اعتماد پیدا ہونا شروع ہوا ۔ اب انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ پھر حدیث کا مطالعہ کیا اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اپنا سابقہ منصوبہ ادھورا چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ انہوں نے اپنا نام عبدالرحمن رکھا اور پورا نام عبدالرحمن مدینہ لولیرا ہے۔ میں ان سے کئی بار ملا ہوں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ان کے تجربے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل کمزوری ناواقفی اور اعتماد کافقدان ہے۔ بعض اوقات ایسے عجیب وغریب راستے سے بھی انسان اسلام کی جانب آ جاتا ہے کہ بظاہر اسلام کی مخالفت پرکام شروع کیا جو اسلام کی منزل پر منتج ہوا۔
ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں جو امریکی ہیں، انتہائی پرجوش مسلمان ہیں۔ وہ دراصل فلسفے کے طالب تھے۔ فلسفہ کا مطالعہ کرتے مسلم فلاسفہ سے متعارف ہوئے، پھر تصوف اور شیخ محی الدین ابن عربیؒ سے مانوس ہوئے۔ عربی کتابیں پڑھتے پڑھتے تصوف کی طرف مائل ہو گئے اور صوفیائے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے مطالعے سے محدثین کے مطالعے کاشوق پیدا ہوا اور محدثین سے مفسرین تک آگئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے کسی بھی راستے سے کوئی شخص دین کے قریب آ سکتا ہے۔‘‘ (ص ۸۲)
عربیت اور قرآن کا گہرا ربط ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک ارشاد گرامی کامفہوم ہے کہ عربی سے تین وجہوں سیمحبت کرو: میری زبان عربی ہے، قرآن عربی میں ہے اور اہل جنت بھی عربی بولیں گے۔ قرآن مجید کے لیے عربی زبان کا انتخاب محض اتفاق نہیں بلکہ عربی کی بحیثیت زبان کچھ خصوصیات ہیں۔
’’ ایک آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیوں اختیار کی گئی؟ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے۔ وہ انسان کا بھی خالق ہے اور اس کی زبان کا بھی۔ نزول قرآن کے وقت بڑی بڑی ترقی یافتہ زبانیں موجود تھیں، یونانی، سریانی، عبرانی وغیرہ۔ ان سب زبانوں میں مذہبی ادب موجود تھا۔ ان سب کو چھوڑ کر عربی زبان کا انتخاب کس بنیا د پر عمل میں آیا؟ اس سوال پر اگر تھوڑا سا غورکریں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک نازل کیا جانا تھا اوراس کے ذریعے سے بے شمار نئے تصورات دیے جانے تھے، اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا گیا جو ایک طرف اتنی ترقی یافتہ ہو کہ قرآن جیسی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تحمل کر سکے اور انہیں اپنے اند ر سمو سکے اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری تھاکہ اس زبان میں کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہوں اور نہ ہی اس زبان پر کسی غیر اسلامی نظریہ کی چھاپ ہو۔ ہر زبان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ انگریزی زبان کا ایک مزاج ہے۔ فرانسیسی، ہندی، سنسکرت وغیرہ زبانوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کسی زبان کا یہ مزاج اس قوم کے عقائد، تصورات اور خیالات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی ز بان کا مزاج ایسا ہے کہ اگر آ پ اس میں ایک گھنٹہ بھی بات کریں اور کوئی صاف بات نہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سننے والا سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات مثبت ہے یامنفی ہے۔ تائید میں ہے یا تردید میں ہے۔ دوستی میں ہے یا دشمنی میں ہے۔ کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ یہ حیلہ گری اور شعبدہ بازی صرف انگریزی زبان ہی میں ممکن ہے، کسی اور زبان میں ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ صدر بش کے ساتھ ہیں یا صدر صدام کے تو اگر اس کا جواب اردو میں دیں تو آپ کو ہاں یا نہیں میں واضح اور دو ٹوک اندا ز میں کہنا پڑے گا۔ لیکن انگریزی زبان ایسی زبان ہے کہ آپ اس کے جواب میں ایک گھنٹہ بھی بولیں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس زبان کا خاصہ ہے۔ اسی طرح ہر ز بان کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے لیے ایسی زبان کا انتخاب ضروری تھا کہ جو ایک طرف تو مکمل طور پر ترقی یافتہ ہو اور دوسری طرف اس پر کسی غیر اسلامی عقیدے یا تصور کی چھاپ نہ ہو۔ عربی کے علاوہ اس وقت کی تمام ز بانوں پر غیر اسلامی عقائد وخیالات کی گہری چھاپ موجود تھی۔ عربی ز بان ترقی یافتہ بھی تھی اور ایسی ترقی یافتہ کہ آج تک کوئی ز بان اس مقا م تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ اس پر کسی غیر اسلامی عقیدے یا نظریے کی چھاپ نہیں تھی۔ ایک اعتبار سے یہ کنواری زبان تھی۔‘‘ (ص: ۱۱۴)
متون اور عبارات کی تشریح وتفسیر کے مسلمہ اصول وضوابط موجود ہیں۔ علم اصول فقہ دراصل تشریح وتعبیر ہی کے قوانین ہیں جو آغاز میں تفسیر قرآن کے لیے مرتب کیے گئے اور پھر انہیں مستقل علم وفن کی حیثیت دے دی گئی۔ علم تفسیر کی تاریخ ومقاصد پر یوں روشنی ڈالی گئی:
’’اس کتاب سے راہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے اور منطبق کرنے میں ان اصولوں اور قواعد کی پابندی کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تفسیر وتشریح قرآن کے لیے برتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرامؓ کے اجتماعی طرز عمل اور امت مسلمہ کے اجتماعی رویہ، تعامل اور فہم قرآن کی روسے تفسیر قرآن کے لیے ایسے مفصل اصول اور قواعد طے پاگئے ہیں جن کی پیروی روز اول سے آج تک کی جا رہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصدیہ ہے کہ جس طرح کتاب الٰہی کا متن محفوظ رہا، اس کی زبان محفوظ رہی، اسی طرح اس کے معانی اور مطالب بھی ہر قسم کی تحریف او راشتباہ سے محفوظ رہیں او ر اس بات کا اطمینان رہے کہ کوئی شخص نیک نیتی یا بد نیتی سے اس کتاب کی تعبیر وتشریح طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر من مانے انداز سے نہ کرنے لگے۔ کسی بھی قانون، کسی بھی دستورکی تشریح وتعبیر اگر من مانے اصولوں کی بنیاد پر کی جانے لگے تو دنیا میں کوئی نظام ہی نہیں چل سکتا۔ جس طرح دنیا کی ہر ترقی یافتہ تہذیب میں قانون ودستور کی تعبیر وتشریح کے اصول مقرر ہیں جن کی ہر ذمہ دار شارح پیروی کرتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر وتعبیر کے بھی اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہؓ نے کی، تابعین اور تبع تابعین نے کی، تاآنکہ ان تمام اصولوں کو اکابر ائمہ تفسیر اور اہل علم نے دوسری اور تیسری صدی میں اس طرح مرتب کر دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے پیروی بھی آسان ہوگئی اور قرآن مجید کی تعبیر وتفسیر کے لامتناہی راستے بھی کھلتے چلے گئے۔ قرآن مجید کو من مانی تاویلات کا نشانہ بنایا جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت کی بجائے گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔
اس کتاب سے گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ طے شدہ عقائد، نظریات اور خیالات لے کر آئیں اور ان کو کتاب الٰہی میں اس طرح سمونے کی کوشش کریں اور اس کے الفاظ کی تشریح وتعبیر اس انداز سے کریں کہ اس سے ان کے اپنے عقائد ونظریات اور افکار وخیالات کی تائید ہو۔ گویا خود کتاب الٰہی کے تابع بننے کی بجائے کتاب الٰہی کو اپنا تابع بنائیں۔ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا شکار ماضی کی قریب قریب تمام اقوا م ہوئیں۔ انہوں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کی۔ آسمانی کتابوں کے معانی اور مفاہیم میں رد وبدل کیا اور ان کے احکام کی تعبیر وتشریح اس طر ح من مانے انداز میں کی کہ وہ ان کے اپنے تصورات ونظریات، عقائد وآداب، غلط رسم ورواج، فاسد نظریات اور باطل تقاضوں کے تابع ہو جائیں اور ان چیزوں کو کتاب الٰہی کی ظاہری تائید ملتی رہے۔
یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں بار بار تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ کا یہ ارشاد گرامی احادیث متواترہ میں شا مل ہے کہ جس نے قرآن مجید کے بارے میں محض اپنی ذاتی رائے اور اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی بات کی (یعنی تفسیر قرآن کے قواعد، اصول تشریح، طے شدہ معانی ومطالب سے ہٹ کر کوئی بات اس کتاب سے منسوب کی) وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس انجام سے بچنے کے لیے اہل علم نے دور صحابہ کرامؓ سے لے کر آج تک اس کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کے متن کی طرح اس کے معانی کی بھی حفاظت کی جائے اور ان گمراہیوں کا راستہ بند کیا جائے جن کا یہود ونصاریٰ شکار ہوئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے معانی ومفاہیم، پیغام ومطالب کی اصالت اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے علم تفسیر کی ضرورت پیش آئی۔‘‘ (ص: ۱۵۶)
تفسیری ذخائر میں کلامی، فقہی، منطقی، ادبی، سائنسی، لغوی اور تحریکی رجحانات موجود ہیں اور کچھ تفاسیر جامعیت کا بھی نمونہ ہیں۔ مقبول ترین یا نمائندہ تفاسیر کون سی ہیں؟ یہ ا یک مشکل سوال ہے۔ جواب ملاحظہ فرمائیں:
’’گزشتہ صدی (یعنی چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی) میں جن تفاسیر نے تفسیر ی ادب اور مسلمانوں کے عمومی فکر پر بہت زیادہ اثر ڈالا، ان کے بارے میں تفصیل اور قطعیت سے کچھ کہنا بہت دشوار ہے۔ دو ماہ قبل کی بات ہے کہ کسی مغربی ادارہ سے ایک سوال نامہ آیا جس میں یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوئے کہ بیسویں صدی میں مسلمانوں پر کن علمی اور فکری شخصیات اور نامور لوگوں کے سب سے زیادہ اثرات ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی مذہبی فکر کی تشکیل میں کن شخصیتوں یا عوامل کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے، اس کے بارے میں وہ شاید کچھ معلومات جمع کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اداروں اور نامور شخصیتوں کو خطوط لکھے اور پوچھا کہ دنیائے اسلام کی وہ دس اہم شخصیتیں کون سی ہیں جن کا مسلمانوں پر بہت گہرا اثر ہے اور وہ کون سی دس اہم تفاسیر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مدد کی۔ ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ سوال آیا اور کئی اہل علم حضرات نے بیٹھ کر اس پر غور وخوض کیا۔ انہو ں نے یہ محسوس کیا کہ اس کا تعین کرنا بے حد دشوار ہے۔ بیسویں صد ی کی کون سی وہ تفاسیر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ سب سے زیاد ہ مقبول اور سب سے زیادہ نمائندہ حیثیت کی حامل تفاسیر ہیں، اس لیے کہ ہر تفسیر کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ جن لوگوں نے جو تفاسیر زیادہ پڑھی ہیں یا جو لوگ جس مفسر سے زیادہ مانوس ہیں، ان کے خیال میں وہی تفسیریں اور وہی مفسرین اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور جنہوں نے کسی دوسری تفسیر کو زیادہ پڑھا ہے اور اس کے مفسر سے زیادہ کسب فیض کیا، ان کے خیال میں وہ نمایاں ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام تفاسیر ہی اپنی اپنی جگہ نمایاں ہیں۔
بعض تفاسیر ایسی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا۔ مثلاً مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جسے لاکھوں انسانوں نے پڑھا اور آج بھی لاکھوں قارئین اس کو پڑھ رہے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا اور ایک نیا رجحان تفسیر میں پیدا کیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن جس کے پچیس تیس ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اتنی کثرت سے شاید کسی اور تفسیر کے ایڈیشن نہیں نکلے۔ عرب دنیا میں سید قطب کی فی ظلال القرآن ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس قدر کثرت سے اس کے ایڈیشن نکلے ہیں کہ تعداد کا اب اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، حالانکہ یہ تفسیر جیل میں بیٹھ کر لکھی گئی تھی جہاں ان کے پاس نہ کتابیں تھیں، نہ وسائل تھے اور نہ مآخذ ومصادر تھے۔ انہوں نے اس تفسیر کو اپنے تاثرات کے انداز میں لکھا۔ عربی زبان کے ایک بالغ نظر ادیب کا کہنا ہے کہ بیسویں صدی میں عربی میں کوئی تحریر اتنی جاندار اور اتنی زور دار نہیں لکھی گئی جتنی سید قطب ؒ کی فی ظلال القرآن ہے۔‘‘
یہ انتخاب اور طائرانہ نگاہ فقط محاضرات قرآنی پر ہے۔ وقت اور موقع ملاتو ان شاء اللہ دیگر محاضرات پر بھی مختصر جائزہ پیش کیا جائے گا۔
’’محاضرات فقہ‘‘ ۔ ایک مطالعہ
چوہدری محمد یوسف ایڈووکیٹ
فرمائش پر لکھنا رقص پا بہ زنجیر کی طرح ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک ایسی شخصیت پر جس کی صرف تصویر ہی دیکھی ہو۔ جناب محمود غازی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، مگر ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع نہیں ملا۔ ایک بار الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں تشریف لائے، مگر میں اس روز حاضر نہ ہو سکا۔ البتہ ان کی بعض تحریریں پڑھی ہیں۔ لا کالج کے میرے زمانہ تدریس میں، اسلامی اصول فقہ کا مضمون ملا تو جناب محمود غازی کی محاضراتِ فقہ اپنے مہربان دوست ڈاکٹر محمد اکرم ورک سے مستعار لی۔ اپنی عادت کے مطابق مطالعہ کے دوران میں کتاب کے اہم حصوں کو مختلف رنگین مارکرز کی مدد سے نشان زد کیا۔ مہربان دوست کو جب کتاب واپس کرنے کے ارادے سے دکھائی تو انہوں نے اس ہائی لائٹنگ سے بے زار ہوکر کتاب مجھے تحفے میں عنایت فرما دی۔ ایک کتاب تو تحفہ میں مل گئی مگر لگتا ہے کہ آئندہ کے لیے مستعار کتاب پر مارکرز سے نشان لگانے کی روش ترک کرنا پڑے گی، وگرنہ تحفہ تو ایک بار ہو گیا ہے مگر کتاب کے مستعار ملنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔
جناب محمود غازی کے بارے میں سنی ہوئی اور لکھی ہوئی روایات کی بنا پر جو تاثر ابھرتا ہے، اسے بیان کرنے کے بعد ان کی مذکورہ بالا کتاب کے حوالے سے کچھ عرض کر کے اپنے کلام کو مکمل کر دوں گا۔ محمود غازی صاحب پرویز مشرف کی سلامتی کونسل میں رہے۔ اس کے باوجود ان کے بارے میں کوئی منفی چیز باہر نہیں آئی، وگرنہ اقتدار میں رہنا اور وقار بچا کر رکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس سے ان کی شخصیت میں معاملہ فہمی کی صلاحیت کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگ اسے زمانہ سازی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر کسی نے ایسا نہیں کہا۔ وہ صاف ستھرے اقتدار میں شامل ہوئے اور اسی طرح باہر ہوئے۔
ان کی شخصیت کے بارے میں دوسرا تاثر یہ سامنے آتا ہے کہ وہ کہنی مار کر آگے بڑھنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بر عکس وہ دوسروں کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہ خوبی بہت ہی کم دیکھی گئی ہے۔ پرانے اساتذہ میں یہ خوبی بدرجہ اتم ہوتی تھی۔ استاد کے مزاج میں یہ خوبی بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیگر وجوہات کے علاوہ اس خوبی کی وجہ سے بھی جناب غازی صاحب طلبہ اور اساتذہ میں بہت مقبول ہوئے۔
محاضرات فقہ، فیصل ناشران کتب، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور سے شائع ہوئے۔ یہ کتاب جناب غازی صاحب کے بارہ خطبات کا مجموعہ ہے۔ یہ خطبات ستمبر اکتوبر ۲۰۰۴ء میں قرآن کی مدرسات کو دیے گئے۔ خطبات اشارات کی مدد سے پیش کیے گئے۔ بعد میں ان کو کتابی شکل میں مرتب کیا گیا۔ کتاب کی مجموعی ضخامت ۵۵۶ صفحات ہے۔ اشاعت جون ۲۰۰۵ء میں ہوئی۔ قیمت ۳۲۵ روپے درج ہے۔ موضوع کے اعتبار سے خاصی ضخیم کتاب ہے۔ اردو میں اس موضوع پر اتنا مواد، یکجا صورت میں بہت کم ملتا ہے۔ انداز بیان بہت سادہ ہے، اگرچہ خطبات کے دوران مخاطبین کی جانب سے مزید سلاست کا مطالبہ ہوتا رہا اور جناب غازی صاحب مزید سلاست کے لیے کوشاں رہے۔
خطبات کا یہ مجموعہ معلومات کا خزانہ ہے۔ اس میں جناب غازی نے فقہ کی ترتیب و ارتقا میں تاریخی پس منظر کو بہت خوبی سے بیان کیا ہے۔ تفہیم کے لیے روز مرہ کی مثالوں سے مدد لی گئی ہے۔ دیگر اصول اور نظام ہاے قانون پر فقہ اسلامی کی برتری ثابت کرنے میں مصنف نے بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ ان کا انداز استدلال بڑا جان دار اور موثر ہے۔ اس میں فقہ و قانون کے طلبہ کے لیے استفادے کے بے پناہ مواقع ہیں۔ ہم یہاں خطبات کے عنوانات درج کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔
(۱) فقہ اسلامی، علوم اسلامیہ کا گل سر سبد
(۲) علم اصول فقہ
(۳) فقہ اسلامی کے امتیازی خصائص
(۴) اہم فقہی علوم اور مضامین
(۵) تدوین فقہ اور مناہج فقہاء
(۶) اسلامی قانون کے بنیادی تصورات
(۷) مقاصد شریعت اور اجتہاد
(۸) اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون
(۹) اسلامی قانون جرم و سزا
(۱۰) اسلام کا قانون تجارت و مالیات
(۱۱) مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ
(۱۲) فقہ اسلامی دور جدید میں
ذیلی عنوانات کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب غازی نے موضوع کے کم وبیش ہر پہلو پر اظہار کیا ہے۔ ان عنوانات کے انتخاب میں مخاطبین کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہوئے قدیم و جدید ضروریات کا بھی بھر پور لحاظ رکھا گیا ہے۔
ان خطبات میں دیگر نظام ہاے قانون کا تاریخی پس منظر بڑا اہم اور دلچسپ ہے۔ حمو رابی کا قانون تاریخی طور پر پہلا مرتب مجموعہ قانون ہے۔ اس کا زمانہ تدوین ۱۷۵۰ قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں اس کی تفصیلات ۱۹۰۱ میں دریافت شدہ تختیوں کے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ ڈاکٹر غازی صاحب نے اس قانون کی اہم دفعات کا جائزہ لیا ہے۔ اس قانون کی خوبیوں اور خامیوں کو پیش کیا ہے۔ ان کے خیال میں اس قانون میں بعض دفعات میں الہامی تعلیمات کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، چور کے ہاتھ کاٹنے، بد کاری کی سزا موت اور حق طلاق کا مرد سے متعلق ہونے جیسے احکام کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بالآخر حمو رابی کا قانون ناپید ہوااور آثار قدیمہ کی دریافت کے نتیجہ میں آج کے علماے قانون کے لیے مطالعے کا موضوع بنا۔
اسی طرح انہوں نے رومن لا کے خصائص کا بھی احاطہ کیا ہے۔ اس قانون کا ابتدائی زمانہ ۴۵۰ قبل مسیح ہے۔ اسے کئی بار مرتب کیاگیا۔ پھر یہ قانون ترقی کرتے کرتے روما کے ایک فرمانروا جسٹینین کے دور میں از سر نو مرتب ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ ہے۔ اس تاریخی تناظر میں بعض مغربی حلقوں نے یہ تاثر پھیلایا کہ اسلامی قانون اور فقہ، رومن لا سے ماخذ ہیں۔ زمانی، علاقائی اور مضامین کے حوالوں سے جناب غازی نے اس کی بھر پور تر دید کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ رومن لا میں اشخاص (persons)، اشیا (things) اور اعمال (actions) کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس قانون کی ہر کتاب میں اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جب کہ اسلامی فقہ کی کم و بیش تمام کتابوں میں اس سے بالکل مختلف ترتیب اختیار کی گئی ہے۔
اس کتاب میں بہت ہی قابل قدر مواد موجود ہے۔ پھر اس میں فقہ اسلامی کی بڑی بڑی جدید و قدیم کتب کا تعارف بڑے شاندار انداز میں پیش کیا گیاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں ڈاکٹر حمید اللہ کے خطبات بہاولپور کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جو جدید وقدیم علوم کے طلبہ کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے۔ اپنے موضوع پر یہ شاندار اضافہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کا زیادہ تفصیلی تعارف کرایا جائے، لیکن چونکہ الشریعہ کا خصوصی نمبر پریس میں جانے کو تیار ہے اوروقت کی قلت تفصیلی تعارف کا موقع نہیں دے رہی، اس لیے صرف ایک پہلو سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔
آج کا اہم سوال منتخب قانون ساز اداروں کو اجتہاد کے اختیارات دینے یا نہ دینے کا ہے۔ اس سوال کو جناب غازی صاحب نے اس کتاب میں نظر انداز کیا ہے۔ اس احتیاط سے، شاید وہ اپنے خطبات کو متنازعہ ہونے سے بچانا چاہتے ہوں۔ البتہ اس کتاب میں انہوں اجتہاد، اس کی حریت اور سرکاری اثرات اور کنٹرول سے آزادی، پر تاریخی پس منظر کی اتنی زیادہ تفصیل دی ہے کہ ان کے نقطہ نظر کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ خاص طور پر اس وجہ کی بنا پر کہ انہوں نے اتنے ضخیم خطبات میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جس سے سرکاری سطح پر اجتہاد کی گنجائش کا شائبہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہو۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال کے خطبات کے چند جملوں کی آڑ لینے میں، منتخب اسمبلیوں کے لیے حق اجتہاد کے کا دعویٰ کرنے والوں نے انتہا کر دی ہے۔ اس بارے میں اقبال کی دیگرتحریروں کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس پہلو سے جناب محمود غازی نے اقبال کے حوالے سے کہا ہے:
’’انہوں نے ۱۹۲۵ میں یہ لکھا کہ میرے نزدیک مذہب اسلام، اس وقت زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ احکامِ قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کیا جائے اور جو شخص زمانہ حال کے جوریس پروڈینس پر تنقیدی نگاہ ڈال کر یہ ثابت کرے گا کہ قرآنی احکام ابدی شان رکھتے ہیں ، وہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن اور دور جدیدکا سب سے بڑا مجدد ہوگا۔‘‘ (ص ۵۲۵)
’’علامہ کے نزدیک اس کام کی جو اہمیت تھی، اس کا اندازہ ان کی تحریرسے بخوبی ہوجاتا ہے۔وہ خودیہ سمجھتے تھے کہ اس کام کودنیاے اسلام کے علمی منصوبوں میں اولین ترجیح حاصل ہوناچاہیے۔ مطالعہ شریعت کے اس پہلوپر طویل غور خوض کے بعدوہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس عظیم کام کا بیڑاان کو خود ہی اٹھانا چاہیے۔ ظاہرہے کہ اپنی غیر معمولی بصیرت، قانون دانی، عربی اور انگریزی سے واقفیت کی وجہ سے اور سب سے بڑھ کر اس وجہ سے کہ سب سے پہلے انہی کو اس ضرورت کا احساس ہوا، وہ دوسروں سے کہیں بڑھ کر اس کام کو انجام دے سکتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ بجائے انفرادی طور پر اس کام کو کرنے کے، اجتماعی طور پر کیاجائے۔‘‘ (ص ۵۲۵)
چنانچہ انہوں نے علامہ سید انور شاہ، مولانا شبلی نعمانی، مولانا سید سلیمان ندوی اورمولانا مودودی کو اپنے منصوبے میں شامل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کوشش کے سلسلے میں:
’’آخر میں انہوں نے مشرقی پنجاب کے ضلع پٹھان کوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صاحب ثروت مخلص بزرگ (چودھری نیاز علی) نے اس ادارہ کے لیے زمین بھی دے دی۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ ایک نوجوان عالم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو بلایا جائے۔ طے یہ ہوا کہ مولانا مودودی وہاں رہیں گے۔ علامہ بھی سال میں چھ مہینے کے لیے وہاں جا کر رہاکریں گے اوروہاں بیٹھ کر دونوں حضرات اپنی اجتماعی کوشش سے نوجوان علما کوتربیت بھی دیں گے اورفقہ اسلامی کی تدوین نو کا کام بھی کریں گے اور یوں جدیددورکی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے فقہ اسلامی کے قواعد و ضوابط وکوازسرِ نو مرتب کیاجائے گا۔ ‘‘ (ص ۵۲۵)
’’اس کی شکل علامہ اقبال کے ذہن میں کیا تھی؟ وہ کن خطوط پر یہ کام کرنا چاہتے تھے؟ اس کے بارے میں قطعی اور حتمی اندازہ کرنا توبہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس موضوع پر ان کی کوئی تحریر موجودنہیں۔ غالباً وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی قوانین کو اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ ان کے اپنے الفاظ میں احکام قرآنیہ کی ابدیت ثابت ہو۔ دورجدیدکی جیورس پروڈنس پر تنقیدی نگاہ بھی ڈالی گئی ہو اور اس کی کمزوریوں کو واضح کیا جائے۔ ....اس کے لیے مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی حیدر آباد دکن میں اپنا گھر بارچھوڑکر، مکان وغیرہ فروخت کر کے اور سب کچھ سمیٹ کر حیدر آباد سے لاہور پہنچے تویہ غالباً جنوری۱۹۳۸ کا واقعہ ہے۔وہ علامہ اقبال سے ملتے ہوئے پٹھان کوٹ گئے۔ لاہور میں کئی دن ان سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ طے ہواکہ علامہ کی صحت جیسے ہی بہتر ہو گی وہ پٹھان کوٹ کا سفر کریں گے۔ لیکن اپریل ۱۹۳۸ میں علامہ کا انتقال ہوگیا۔ اس کام کا نہ تو ابتدائی خاکہ ہی تیار ہو سکا اورنہ کام کا آغاز ہی ہو سکا۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دنیائے اسلام کے اس عظیم فرزند اور مفکر کی نظرمیں اس کام کی کتنی اہمیت تھی۔‘‘ (ص ۵۲۵)
علامہ کی اس کوشش کو جناب غازی اجتماعی کوشش کے طور پر ذکرکرتے ہیں۔ جناب غازی صاحب نے بھی کہا ہے کہ علامہ اس کام کو خود انجام دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ علما کی معاونت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس میں مولانا مودودی کے سوا کسی نے علامہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیاتھا۔
ابتدائی زمانہ میں فقہ کی ترتیب کی ضرورت کے حوالے سے جناب غازی نے ارشاد فرمایا:
’’جب دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوا اور دنیائے اسلام کی حدود، دن بدن پھیلتی چلی گئیں تو روزانہ ایسے مسائل پیش آتے تھے جن کے جوابات شریعت کی روشنی میں درکار تھے۔ آئے دن ہر بڑے چھوٹے شہر اور بستی میں نئی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔ ان حالات میں اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ کسی قابل اعتماد اور مستند فقیہ کی عدم موجودگی میں لوگ کم علمی سے غلط فیصلے نہ کردیں۔ یا کسی کم علم آدمی سے جا کر پوچھنے لگیں اور کوئی غلط رائے قائم کر لیں۔ اس زمانے میں دنیائے اسلام کی حدود چین سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اسپین اور فرانس کی سرحد کے درمیان ’لے پیرینے‘ نام کا ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے۔ اس کی حدود سے لے کر پورا اسپین، آدھا پرتگال، پورا شمالی افریقہ، پورا مشرق وسطی، پور افغانستان، پورا وسط ایشیا، پورا ایران اور چین کی شمالی سرحد تک دنیائے اسلام کی حدود تھیں۔ اب یہاں اس بات کا امکان ہر وقت موجود تھا کہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی سرحدی علاقے میں، نو مسلموں کے کسی بستی میں، کسی آدمی کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہاں جواب دینے والا کوئی پختہ علم اور پختہ کار فقیہ دستیاب نہ ہو، یا موجود ہو لیکن کچا فقیہ ہو یا کچا بھی نہ ہو لیکن اس معاملہ میں اس کے پاس رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ غلط جواب دے دے۔ یوں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو غلط سمجھ لیں اور غلط طریقے سے عمل کریں۔ ان حالات میں بعض فقہائے اسلام نے یہ محسوس کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے نئے مسائل، سوچ سوچ کر جواب دیا جائے۔ بجائے اس کے، ہم انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی آکر صورت حال اور ممکنہ مسئلہ بیان کر کے شریعت کا مسئلہ پوچھے تو ہم جواب دیں گے۔ ہمیں از خودغور کر کے ممکنہ سوالات اور ممکنہ معاملات فرض کرنے چاہیں اور ان کا جواب تیار کر کے رکھنا چاہیے۔‘‘ (صفحہ نمبر ۴۸)
اسے فقہ تقدیری کہا جاتا ہے۔
جناب ڈاکٹر محمود غازی نے فقہ اسلامی کے ایک اہم امتیازی وصف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ جان آسٹن کے مطابق قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے۔ (Law is the command of sovereign) ۔اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے مروجہ جدید قانون کے مواخذ بیان کرتے ہوئے ماہرین کی تشریحات اور مقننین کے مرتب کردہ قوانین کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ :
’’فقہ اسلامی کی کتابیں ان میں سے کس زمرہ میں آتیں۔ نہ وہ کسی بادشاہ یا فرمانروا کا عطا کردہ چارٹر ہے، نہ کسی سربراہ مملکت کا جاری کردہ آرڈنینس ہے۔ کسی بھی فقہی مسلک کی کوئی بھی کتاب کسی حکمران یا فرمانروا کی دی ہوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی عطا کردہ بھی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین سے زیادہ خدا ترس اور عادل حکمران، دنیا نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ قانون ان کا عطا کردہ فرمان بھی نہیں۔ یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہو اقانون بھی نہیں ہے۔ فقہ کی کوئی بھی کتاب یا کوئی حکم جس پر آج مسلمان عمل کرتے ہیں، وہ کسی پارلیمنٹ کا دیا ہوا نہیں ہے۔‘‘ (ص ۱۱۹)
علامہ غازی فقہ کی ترتیب کے حوالے سے کہتے ہیں:
’’جس زمانے میں لوگوں نے اس کو لکھا، انہوں نے ایک زندہ قانون کے طور پر لکھا۔ فقہ تو ان اہل علم کے لکھنے سے پہلے ہی مسلمانوں کی زندگی میں نافذ العمل تھا۔ امام مالک نے جب موطا لکھی تو اس میں جو احکام دئیے گئے وہ پہلے سے لوگوں کی زندگیوں میں جاری و ساری تھے۔ اگر دو چار احکام ایسے تھے بھی جو بڑے پیمانہ پر لوگوں کی زندگی میں جاری نہیں تھے تو امام مالک کے موطا لکھنے کے بعدجاری و ساری ہو گئے۔ اس لیے موطا میں بیان کردہ قانون، ایک لمحہ کے لیے بھی مردہ قانون نہیں تھا۔ .... یہ خصوصیت ہے جو اسلامی قانون یا فقہ کو دنیا کے تمام قوانین سے ممیز کرتی ہے۔‘‘(ص ۱۲۰)
’’فقہ اسلامی کی یہ سب سے نمایاں اور امتیازی خصوصیت آزادی اور حریت کی صفت ہے۔ ‘‘
’’اسلامی قانون دنیا کا واحد قانون ہے جو حکمرانوں اور فرمانرواؤں کے ہر قسم کے اثرات اور رسوخ سے آزاد رہا۔ اس کی تمام تر ترقی اور پیش رفت، اس کی ساری توسیع، تمام گہرائی اور گیرائی ، وہ سب کی سب غیر سرکاری کاوشوں کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں کبھی بھی کسی سرکاری قانون ساز ادارے کا وجود نہیں رہا۔ ایسا قانون ساز ادارہ جیسے آج دنیاکے بہت سے نظاموں میں پائے جاتے ہیں۔آج برطانیہ میں ایک پارلیمنٹ ہے جو برطانوی لوگوں کے لیے قانون بناتی ہے، اچھا یا برا۔ امریکہ میں کانگریس قانون بناتی ہے۔ ایسی کوئی کانگریس یا ایسی کوئی پارلیمنٹ، کسی اسلامی دور میں نظر نہیں آتی۔ نہ یہ قانون سازی سرکاری اور حکومتی کوششوں کی مرہون منت ہے۔‘‘(ص ۱۲۰)
اس امتیازی خصوصیت کی بنیاد اور حکمت کے ذکر میں جناب غازی صاحب فرماتے ہیں:
’’اللہ تعالی نے ہر انسان کو آزاد بنایا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اس برابری کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک اوریکساں ہو۔ اگر قانون سب کے لیے یکساں نہ ہو توپھر مساوات اور برابری نہیں ہو سکتی۔ .... اگر کچھ انسان دوسرے انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں تو قانون بنانے والے بر تر ہوں گے اور قانون قبول کرنے اوراس پر عمل کرنے والے زیر دست ہوں گے۔ جو قانون بنائے گا وہ اپنی فلاح و بہبود اور اپنے مفاد اور مقاصد کے لیے قانون بنائے گا۔‘‘ (ص ۱۲۱)
جناب غازی صاحب نے اپنے خطبہ میں مغربی قانون میں مابعد الطبیعاتی تصور کا ذکر کیا ہے:
’’یہ تصور تیس چالیس سال پہلے پیدا ہوا ہے۔ اس کے مطابق اصول قانون کے تمام احکام سے ماورا، اعلی اور بر تر فطری تصورات پر، اصول قانون کے تصورات کا دار و مدار ہے۔ جب تک یہ بنیادی اور اساسی قواعد نہ ہوں، جن پر اصول قانون کے احکام کی عمارت اٹھائی جا سکے اس وقت تک خود اصول قانون کا تعین دشوار ہے۔ گویا meta-jurisprudence جیسی اہم اور بنیادی چیز جس پر قانون کی آخری سند اور اساس کا دار و مدار ہے، اس پر مغربی دنیا صرف چالیس پچاس سال پہلے آئی ہے۔ اس سے پہلے اس شعبہ علم کا کوئی تصور مغرب میں نہیں تھا۔ اس کے بر عکس میٹا جورس پروڈینس کے تمام اصول و ضوابط قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ قران پاک نے ان تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے جن پر جورس پروڈینس کی اساس ہوئی ہے۔ یوں وہ بنیادی اصول و ضوابط، جن سے کام لے کر قرآن و سنت سے احکام معلوم کیے جاسکتے ہیں پہلے دئیے گئے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید نے بنیادی سوالات تو ابتدا ہی سے طے کر دیے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہم امور و مسائل میں جہاں جہاں انسان کی عقل کے بھٹکنے اور غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا، ضروری رہنمائی فراہم کر دی ہے اور اہم سوالات کا جواب دے دیا۔ اب رہ جاتاہے مزیدتفصیلات طے کرنے یا روزمرہ کے جزوی مسائل کا جواب دینے کا فریضہ تووہ بھی کسی بادشاہ یاحکمران کے سپردنہیں کیا گیا۔ یہ کام فقہی اجتہادات اور فتاوی کے ذریعے کیاجاتا ہے۔ فتویٰ اور اجتہادکی ذمہ داری شریعت نے فرمانرواؤں کونہیں دی بلکہ یہ ذمہ داری علما اور فقہاکے سپرد کی ہے۔‘‘( ص ۱۲۲)
’’یہی وجہ ہے کہ یہ کام تاریخ اسلام میں نہ کسی فرمانروا نے کیا، نہ بادشاہ نے، نہ خلیفہ نے اورنہ کسی پارلیمنٹ نے۔ اس کام میں سرکار اور دربار کاکبھی کوئی دخل نہیں رہا۔ یہ کام امت اور امت کے اہل علم نے کیا اور انہی کے کرنے کا یہ کام ہے۔ ’’فاسئلوا اھل الذکرا ان کنتم لا تعلمون‘‘ امت کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرے۔ اگر کسی شخص یا گروہ یا جماعت کو کسی معاملہ میں تامل ہو کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے اور شریعت کی فہم کیا کہتی ہے تو وہ جا کر اہل علم سے معلوم کرے۔ اہل علم ایسے ہوں جن کے دین اور علم پر یعنی ان کے علم اور تقویٰ، دونوں پر عامتہ الناس کو اعتماد ہو، ان کی بات مان لی جائے۔‘‘(ص ۱۲۲، ۱۲۳)
’’چنانچہ اسی نظام کے تحت فقہائے امت اور علمائے اسلام نے اس ذمہ داری کو انجام دینا شروع کیا۔ جن جن حضرات کی فقہی آرا کی، مسلمانوں میں روز اول سے پیروی کی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی سرکاری منصب کا حامل نہیں تھا۔ امام مالک نے موطا لکھی اور بہت سے قانون اور فقہی مسائل کے جوابات دئیے۔ ان کے دئیے ہوئے جوابات اور ان کی جاری کردہ رولنگز پر دنیائے اسلام کے بہت بڑے حصے میں امام مالک کے اپنے زمانے سے عمل ہو رہا ہے۔ لوگ امام مالک کے علم اور تقویٰ پر غیر معمولی اعتمادکی وجہ سے ان کے اجتہادات پربھروسہ کرتے تھے اور ان کی فقہی آرا، بالفاظ دیگر ان کی قانون سازی پر عمل درآمد کرتے تھے۔‘‘
’’امام مالک سے لوگوں کی محبت اور عقیدت کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ چھ چھ مہینے کی مسافت طے کر کے امام مالک سے مسائل معلوم کرنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص چھ مہینے کی مسافت طے کر کے اسپین سے مراکش پہنچا۔ وہاں سے تیونس، الجیریا، لیبیا، مصر، صحرائے سینا اور پورے جزیرہ عرب کاآدھا حصہ سفر کر کے طے کیا، یہ سب وسیع علاقے عبور کر کے مدینہ منورہ پہنچا اور امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مجھے اہل اندلس نے آپ سے یہ سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے‘‘۔ (ص ۱۲۳)
’’اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک سے اہل اندلس کی عقیدت کی کیفیت کیا تھی اور امام مالک کے فتاوی اور ارشادات پرکتنی شدت سے اہل مغرب اوراہل اندلس عمل کرتے ہوں گے۔ کیا امام مالک کسی علاقہ کے فرمانرواتھے؟ کیا ان کوکسی خلیفہ نے مقرر کیا تھا کہ آپ اہل اندلس کے لیے قوانین بنائیں؟ کیاوہ کسی پارلیمنٹ کے رکن تھے؟ کیا وہ کسی کانگریس کے رکن تھے؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ امام مالک ایک پرائیویٹ شہری تھے۔ ایک مکمل غیر سرکاری حیثیت رکھتے تھے۔ ان کو اللہ نے جو درجہ دیا وہ صرف ان کے علم اور تقویٰ کی وجہ سے تھا۔ علم اور تقویٰ کے علاوہ کوئی دنیاوی منصب یا عہدہ یا اختیار ان کو حاصل نہیں تھا۔ لوگ ان کے فتوی اور ان کی دی ہوئی رولنگز پرعمل کرتے تھے۔ عدالتیں بھی عمل کرتی تھیں اور افرادبھی کرتے تھے اور حکمراں بھی کرتے تھے۔‘‘ (ص ۱۲۳، ۱۲۴)
’’امام اوزاعی امام اہل الشام کہلاتے تھے۔ وہ بیروت میں رہتے تھے اورایک زمانے میں پورا شام جس میں موجودہ فلسطین، لبنان، اردن اور شام اور شمالی سعودی عرب کا کچھ حصہ شامل تھا۔ یہ پورا علاقہ امام اوزاعی کے اجتہادات کی پیروی کرتا تھا۔ یہاں تک کہ حکمرانوں کوبھی جب ضرورت پڑتی تھی وہ امام اوزاعی سے فتوی معلوم کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ہارون الرشیدکوکسی ایسے معاملے میں جو بین الاقوامی قانون سے متعلق تھا، جس میں ایک غیر قوم کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا، اس میں بین الاقوامی ذمہ داریوں کی قسم کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ معاہدہ رائے دینے کے لیے امام اوزاعی کو بھیجا اور انہوں نے جورائے دی، ہارون نے اس کے مطابق عمل کیا۔ کیا امام اوزاعی، سلطنتِ عباسی کے وزیر خارجہ یا وزیرقانون تھے؟ کیاوہ وہاں کے چیف جسٹس تھے؟ بالکل نہیں، وہ ایک عام شہری تھے۔‘‘ (ص ۱۲۴)
’’امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کی پیروی آج دنیابھر میں مسلمان بڑی تعداد میں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کی پیروی کررہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں تھا۔ امام جعفر صادق، امام زید بن علی اور تمام مجتہدین کرام، سب حضرات عام شہری تھے اور علم و تقویٰ کے علاوہ ان میں اور عامتہ الناس میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔‘‘ (ص ۱۲۴)
’’طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی شخص کوکوئی مسئلہ پیش آئے، وہ ان میں سے جس فقیہ یاجس مجتہد کے علم اور تقویٰ پر اعتماد کرتے ہوں، اس کے فتوی کے مطابق عمل کریں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں۔‘‘ (ص ۱۲۴)
’’جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس میں آپ کو شریعت کے کسی معاملہ میں رہنمائی یا شریعت کے کسی حکم کی تعبیر کی ضرورت ہو تو آپ یا میں کسی وزیر قانون کے پاس نہیں جاتے۔ عدلیہ کے کسی افسر کے پاس نہیں جاتے۔ پارلیمنٹ کے کسی ممبر کے پاس نہیں جاتے۔ ہم صرف اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے علم اور تقویٰ پرہمیں اعتماد ہو۔‘‘(ص ۱۲۴)
’’اس طریقے سے فقہ اسلامی اور شریعت اسلامی پر عمل درآمد کوئی بارہ سو سال تک ہوتارہا۔ ان بارہ سو سالوں میں کبھی کسی حکمراں یا فرمانروا کوشریعت کے کسی جزوی حکم پربھی اثر اندازہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگوں نے کوشش کی، کچھ نے اچھے ارادے سے کوشش کی اور کچھ نے برے ارادے سے کوشش کی، لیکن مسلمان فقہانے ایسی کسی کوشش کوکامیاب ہونے نہیں دیا۔‘‘(ص ۱۲۵)
’’ہارون رشید نے جب اسپین سے ملتان تک پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت میں موطاکو بطور قانون رائج کرنے کی اجازت امام مالک سے طلب کی تو امام صاحب نے ہارون رشید کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ وسیع تر سلطنت میں جتنے بھی فقہا اور مجتہدین، اجتہادات اور فیصلے کر رہے ہیں، یہ سب کے سب مختلف صحابہ کرام کے اسلوب کی پیروی کررہے ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، اجتہاد کی تربیت پائی، شریعت پر غور و خوض کرنے کے آداب سیکھے اوروہ دنیائے اسلام کے مختلف علاقوں میں جا کربس گئے جہاں انہوں نے اس اسلوب کے مطابق لوگوں کو تیار کیا۔ اس لیے یہ سارے کی ساری آرا اور تعبیرات صحابہ کرام تک اور ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے آپ اس آزادی کو، جو امت مسلمہ کو حاصل ہے محدود نہ کریں اور جس انداز سے کام چل رہاہے، اسی انداز سے چلنے دیں۔ غرض امام مالک نے ہارون کی رائے سے اتفاق نہیں فرمایا اور قانون کی آزادی اور خود مختاری پرایک ہلکا سا دھبہ بھی آنے نہیں دیا۔ یہ فقہ اسلامی کی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جس کو حریت قانون سازی یا آزادی کہہ سکتے ہیں۔‘‘ (ص ۱۲۷)
قانون سازی کی حریت یا آزادی کے تحفظ کی فکر اہل علم میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کی ایک کوشش کا ذکر جناب غازی اس طرح فرماتے ہیں:
’’سب سے پہلے رابطہ عالم اسلامی نے مکہ مکرمہ میں ایک فقہ اکیڈمی قائم کی۔ اس میں دنیائے اسلام کے مختلف علاقوں کے نامور فقہا کو جمع کیا گیا اور یہ تمام مسائل ان کے سامنے رکھ دیے گئے اور ان سے کہاگیا کہ وہ اب ایک عملی دستور العمل اور ہدایات تیارکریں جن میں ہر چیز کے بارے میں الگ الگ بتایا گیاہو کہ کیا کرنا ہے۔‘‘
’’رابطہ عالم اسلامی ایک غیر سرکاری ادارہ ہے، اس لیے اس کی فقہ اکیڈمی نے جو مشورے دیے اور جو دستاویزات تیار کیں، ان کی حیثیت بھی ایک غیر سرکاری اور پرائیویٹ قسم کی تھی۔‘‘ (ص ۵۳۳)
تاریخ اسلام میں شخصی سطح پر قانون سازی کی آزادی کا تواتر اسے ایک بنیادی قدر بنا دیتا ہے۔ اجتہاد کی سرکار دربار سے آزادی ہمارا تاریخی اثاثہ ہے۔ یہ اثاثہ بارہ صدیوں پر محیط ہے۔ اسے کسی صورت قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ائمہ کبار کی عظیم الشان قربانیوں سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ ان کی استقامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب غازی صاحب نے اپنے خطبات میں اس قدرِ حریت کو بڑی خوبی سے واضح کیا ہے۔ ان کا پیرایہ بیان براہ راست کے بجائے بالواسطہ ہے۔ ان کا آہنگ دھیما ہے۔ وہ مخاطب کے ذہن کو غیر محسوس طور پر متاثر کرتے ہیں، لیکن ان کا پیغام ان کے بالواسطہ خطبات سے چھن چھن کر آتا ہے۔ ان کی جانب سے یہ یاد دہانی ہے۔ دور غلامی میں یہ آزادی سلب ہوئی، غلامی سے نجات کے بعد یہ آزادی بحال نہیں ہو سکی۔ کوئی ہے جو اس آزادی کا چراغ جلا سکے!
محاضراتِ معیشت و تجارت کا ایک تنقیدی مطالعہ
پروفیسر میاں انعام الرحمن
اپنی کلاسیکل علمی روایت کے ساتھ شعوری وابستگی عصرِ حاضر میں جن اصحاب کے حصے میں آئی ہے، ڈاکٹر محموداحمد غازی مرحوم ان میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ مرحوم کے محاضرات خواص و عوام میں پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ اگر مسلم علمی روایت کے اس پہلو کو پیشِ نظر رکھا جائے کہ اس میں زبان و بیان، قلم و قرطاس پر چھائے رہے تو ڈاکٹر غازی ؒ اس روایتی پہلو کے جدید ترین نمائندہ تھے۔ ان کے محاضرات کا توضیحی و تنقیحی اسلوب گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے ’’نگہ بلند،سخن دل نواز،جاں پرسوز‘‘ کے ساتھ اسلاف کے علمی کارنامے نئی نسل تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور درجات بلند فرمائے،آمین۔ اس وقت ہمارے پیش نظر ڈاکٹر محمود مرحوم کی کتاب ’’محاضراتِ معیشت و تجارت‘‘ ہے جو اسلامی معاشیات پر ان کے بارہ خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس کے صفحات ۴۵۹ ہیں اور قیمت۵۰۰ روپے ہے۔ الفیصل ناشران لاہور نے اسے شائع کیا ہے۔
ڈاکٹر غازی مرحوم علمی دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے ’’تقدیم‘‘ کی سطروں میں کھلے عام اعتراف کرتے ہیں کہ وہ معاشیات میں کسی مہارت کے مدعی نہیں ہیں۔ ان کا یہ اعتراف فنِ معاشیات کا باقاعدہ یا بے قاعدہ طالب علم نہ ہونے تک پھیلا ہواہے۔ وہ بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جدید فنی معاشی مسائل سے ان کی واقفیت سرسری اور جزوی ہے، اس لیے وہ ماہرین معاشیات سے بلا جھجھک درخواست کرتے ہیں کہ ان محاضرات کی فنی خامیوں اور کم زوریوں سے درگزر کریں، نیز ان کی نشاندہی کر کے راہنمائی بھی فرمائیں۔ ہم حیرت سے کبھی اعتراف نامہ دیکھتے ہیں اور کبھی ان محاضرات کے مندرجات۔ یہ مندرجات گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے ممدوحؒ کا اعتراف نامہ اسلاف کے طرزِ عمل کی پیروی ہے، وگرنہ محاضرات تو فکری و فنی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو ایک خاص آسانی سے نوازا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں عملی راہنمائی درکار ہو تو فوراًسے پہلے ہم اسوہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اس لیے ان کی نظریں بھی خود بخود اسی مرکز کی جانب اٹھ جاتی ہیں:
’’خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بہت بڑی تجارت قائم فرمائی تھی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کامیاب نگرانی فرمائی۔ اس کی آمدنی کا بیشتر حصہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں پر خرچ ہوا۔‘‘ (دوسرا خطبہ: ص ۷۴)
ڈاکٹر غازیؒ نے یہ اشارہ تو کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی آمدنی کا زیادہ حصہ دعوت و تبلیغ میں صرف ہوا، لیکن موضوع کی مناسبت سے یہ وضاحت نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملاتِ تجارت کیسے نمٹائے ، تجارت میں منافع کی شرح کیا رکھی اور حضرت خدیجہؓ کے ساتھ منافع کی تقسیم کس اصول کے تحت اور کتنے فی صد طے پائی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس قسم کے سوالات سے تعرض کرتے تو آج کے تاجروں کے لیے ہدایت کا مینارہ نور قائم کر دیتے۔ اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری نے اپنی کتاب ’’نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی‘‘ میں فقط اتنا اضافہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامانِ تجارت لے کر شام کا دوسرا سفر کیا تو یہ مضاربت سے زیادہ اجارہ کی ایک صورت تھی، کیونکہ حضرت خدیجہؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین اجرت ادا کی تھی جو کہ ایک اونٹ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاوہ یمن اور بحرین کے بھی تجارتی سفر کیے جن کی بابت تاحال زیادہ تفصیلات میسر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری نے حلف الفضول کو بھی معاشی تناظر میں دیکھنے کی قابل غور کوشش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل تقریباً ۲۰ برس کی عمر میں ایک ایسے معاہدے میں شمولیت فرمائی جس کی نوعیت سراسر معاشی و سماجی انصاف کی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصبِ نبوت پر فائز ہونے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس قسم کے معاہدہ کی طرف آج بھی دعوت دی جائے تو میں بخوشی شامل ہونے کو تیار ہوں گا۔ اس معاہدے میں مضمر مخصوص خیر کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا۔ لہٰذا ما قبل نبوت کا یہ تناظر پورا قرینہ فراہم کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں معاشی سرگرمی کی خاص اہمیت ہے۔ اسی لیے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا منصب سنبھالنے سے قبل خالصتاً بشری حیثیت میں صرف تجارت نہیں بلکہ تجارت کا سفر کیا اور متاہل زندگی (married life) بسر کی اور کاروبار و شادی کے مراحل سے گزرنے کے باوجود مخالفین کی نظر میں امین و صادق کہلائے۔ ہمارے ہاں الطاف حسین حالی مرحوم کے کہے مصرعے ’’اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا‘‘ کو کچھ اس طرح رومانوی روپ دے دیا گیا جس سے مجموعی طور پر دین اسلام کے حقیقی مزاج سے مغایرت وبے گانگی (alienation) کے رویے نے خوب فروغ پایا۔ حالانکہ امرِ واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کی خو بو اور مزاج کا صحیح پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ متاہل زندگی بسر کرے یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا مال و دولت کا کوئی معاشی معاملہ طے کیا جائے۔ معاملہ طے کرنے کے دوران میں اور طے پا جانے کے بعد اس کا رویہ اس کے حقیقی مزاج کی خبر کرتا ہے۔ چونکہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں ہیں بلکہ بشر بھی ہیں اور بشر کی ارضی زندگی میں ازدواجی و معاشی سرگرمی بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس ازدواجی و معاشی سرگرمی کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کرنے اور انہی سے پھوٹتے بشری رویے کو تدین کا معیار بنانے کی خاطر، اللہ رب العزت نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالصتاًبشری حیثیت میں معاشی انصاف پر مبنی معاہدے اور تجارت و سفر تجارت اور شادی جیسے مراحل سے گزارا ۔ ذرا غور کیجیے کہ تجارت و سفرِ تجارت اور متاہلانہ زندگی (بشمول بیٹیوں کا باپ ہونے اور ان کی شادیاں تک کر دینے) کی جاں گسل راہ سے گزار کر، اس وقت کے معاشرے کو ایک ’’بشری معیار‘‘ دینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو ختمِ نبوت کے منصب پر فائز فرمایا گیا۔ ہمارے موقف کی تنقیح حضرت سائبؓ کے اس بیان سے ہوتی ہے جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دیا تھا۔جب وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صحابہ کرامؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس پر سائب نے کہا کہ:
صدقت بابی انت وامی، کنت شریکی فنعم الشریک کنت، لا تداری ولا تماری (ابوداود، رقم ۴۸۳۶)
’’میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ نے درست فرمایا۔ آپ میرے شریک تجارت تھے اور آپ نہ تو جھگڑا کرتے تھے اور نہ بحث کرتے تھے۔‘‘
اس گواہی پرذرا غور تو فرمائیے۔ واقعہ یہ ہے کہ دینِ اسلام کی اس اصالت کا اظہار بعد کی صدیوں میں ہوتا رہا جب مسلمان تاجروں نے اپنے ازدواجی و معاشی رویے سے تشکیل پانے والے تدین کی بنیاد پر اسفارِ تجارت کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹرمحمود احمد غازیؒ بجا کہتے ہیں کہ:
’’اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہو گا کہ اسلام اور تجارت اور اسلام اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔‘‘ (دوسرا خطبہ: ص ۷۴)
اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے ابن العربیؒ کا قول پیش کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن العربیؒ کتنے معروضی انداز میں (objectively) دین اسلام کا حقیقی مزاج دیکھ رہے تھے:
’’انسانی ترقی کا دارومدار یا انسان کی بقا کا دارومدار جن معاملات پر ہے، ان میں مشہور مالکی فقیہ اور مفسرِ قرآن علامہ ابن العربیؒ کے بقول عقدِ نکاح اور عقدِ بیع دو بنیادی اہمیت رکھنے والے معاملات ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں: ’’یتعلق بھما قوام العالم‘‘ دنیا کی پوری زندگی کی بقا ان دونوں پر موقوف ہے۔‘‘(چھٹا خطبہ:ص۲۶۱)
لہٰذا دینِ اسلام کی ایسی تعبیر جس کے مطابق دینی عقیدہ، سماجی زندگی کے رگ و پے میں اترنے کے بجائے رسوم و عبادات کے شبستانوں میں خوابِ خرگوش کا مزہ لیتا رہے، ہرگز قابلِ قبول نہیں ہو سکتی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے ایک شخص کو عبادت و ریاضت میں ڈوبا ہوا دیکھا تو اسے درہ رسید کرتے ہوئے فرمایا: ’’اللہ تیرا برا کرے، ہمارے دین کو مردہ بنا کر پیش نہ کر‘‘۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے دور میں عبادت و ریاضت میں گھلے جانے والے کو دین زندہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسی ریاضت پسند اور عبادت گزار شخص سے جب کوئی معاملہ کیا جائے تو تدین اور موصوف، بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمرفاروقؓ کے دور کا ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص بطور گواہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے کسی ایسے شخص کو لانے کو کہا جو اسے جانتا ہو۔ وہ ایک شخص لایا جس نے اس کے بارے میں بہت اچھی رائے کا اظہار کیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم اس کے ہمسائے ہو اور اس کی زندگی سے خوب واقف ہو؟اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا ، کیا تم نے اس شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا،میرا خیال ہے کہ تم نے اسے مسجد میں کھڑے قرآن پڑھتے، کبھی سر جھکاتے، کبھی اوپر اٹھاتے دیکھا ہے۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ تب آپ نے فرمایا، چلے جاؤ تم اس کو بالکل نہیں جانتے اور اس شخص کو حکم دیا کہ جاؤ اور کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو تمہیں ’’واقعی‘‘ جانتا ہو۔ غور کیجیے، یہ واقعہ خلیفہ دوم فاروقِ اعظمؓ کا ہے جو دینِ اسلام کے حقیقی مزاج کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ دین کی زندہ متحرک اور سماج سے وابستہ یہ تعبیر سیدنا عمر فاروقؓ کے بعد بھی جاری و ساری رہی۔ ڈاکٹر غازی مرحوم تاریخ کے جھروکے سے پردہ اٹھاتے ہیں:
’’مشہور تابعی فقیہ اور حضرت امام ابوحنیفہ ؒ کے استاد الاستاذ ابراہیم نخعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ سچا دیانت دار تاجر مجھے زیادہ محبوب ہے بہ نسبت اس شخص کے جو سب کام چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے کہ جو شخص تجارت کرتا ہے ، زندگی کی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے انجام دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتا ہے، دینی ذمہ داریاں بھی انجام دیتا ہے۔ وہ مسلسل جہاد کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ جہاد جو اس کا اپنے نفس کے خلاف ہے، شیطان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم نخعیؒ نے کہا کہ شیطان طرح طرح سے اس تاجر کے سامنے آتا ہے، کبھی ناپ تول اور ترازو کے ذریعے آتا ہے، کبھی لین دین کے ذریعے سامنے آتا ہے اور اس کو راہِ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیانت دار تاجر شب و روز شیطان کے ان حربوں کو ناکام بنانے میں مصروف رہتا ہے اپنے کو ان سے دور رکھتا ہے اپنے طرزِ عمل کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ یوں اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے اور تزکیہ کے نتیجے میں جو کھرا پن پیدا ہوتا ہے، جو ستھرا مزاج انسان کا بنتا ہے، وہ اس شخص کا نہیں ہوسکتا جو سب کام چھوڑ کر مسجد کے گوشے میں یا خانقاہ کے گوشے میں بیٹھ گیاہو۔‘‘ (چھٹا خطبہ:ص۲۵۱،۲۵۲)
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کی پر خطر راہ سے گزر کر تزکیہ حاصل کرنے کے بجائے کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر متقی کہلانے والوں کے لیے ہی علامہ مرحوم نے کہا تھا:
جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا!
کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارہ یا کہ زجاج
معاشی سرگرمی پر مبنی دین کی متحرک تعبیر کا ایک اور دلچسپ واقعہ ڈاکٹر غازیؒ نے پیش کیا ہے، ملاحظہ کیجیے:
’’مشہور محدث حضرت ابو قلابہؒ جو علمِ حدیث کی تاریخ کی نمایاں شخصیتوں میں سے ہیں، جن کی سند سے بہت سے ائمہ حدیث کو بہت سی روایات ملی ہیں، انھوں نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر تلاوت اور عبادت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ذریعہ آمدنی کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ ہدیہ دیتے ہیں، وہ استعمال کرتا ہوں اور اپنا وقت عبادت میں صرف کرتا ہوں۔ ابوقلابہؒ نے کہا کہ: ’’لان اراک تطلب معاشک احب الی من ان اراک فی زاویۃ المسجد‘‘، میں تمہیں معاشی زندگی اور رزقِ حلال کے حصول میں سرگرم دیکھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں تمہیں مسجد کے گوشے میں بیٹھے دیکھوں۔ اس لیے کہ عبادت کا اپنا وقت ہے معاشی سرگرمی کا اپنا وقت ہے، دونوں کی ذمہ داریاں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ ایک کو دوسرے کے لیے قربان کرنا یہ شریعت کے توازن اور اعتدال کے خلاف ہے۔‘‘(چھٹا خطبہ:ص۲۵۳)
ہمیں ابوقلابہؒ کی خوش بختی پر رشک آ رہا ہے کہ ان کے دور میں تبلیغی جماعتوں کے ا جتماع منعقد نہیں ہوتے تھے جہاں سے اب دین کی وہی تعبیر بڑے منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے جس کی نفی ابوقلابہؒ کر رہے تھے۔ اگر وہ عبادت گزار تبلیغی جماعت سے وابستہ کوئی فرد ہوتے تو اپنے عجیب و غریب جواب سے ابوقلابہ صاحب کی قلابازیاں لگوا دیتے۔ خیر! یہ قلابازیاں تو مفروضے پر مبنی ہیں اور ’’اگرمگر‘‘ کی شرط کے ساتھ ہیں، لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے نام نہاد متقیوں کی قلابازیاں واقعی لگوا دی ہیں۔ دیکھیے ذرا:
’’ یہی وجہ ہے کہ علمائے اسلام نے یہ لکھا تھا کہ تجارت انسان کی کسوٹی ہے۔ انسان کے تدین، تقویٰ اور پرہیز گاری کا امتحان، لین دین اور تجارت میں ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص پوری زندگی تدین کا رویہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ نمازیں روزے عبادات اور تمام مذہبی سرگرمیوں کی پوری پابندی کرتا ہے۔ یہ سب کام اس کے ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اس کو کبھی بھی کسی سے لین دین کا اتفاق نہیں ہوتا۔ جب لین دین کا اتفاق پہلی مرتبہ ہو جائے تو پتا چلتا ہے کہ کتنا زرپرست انسان ہے۔ ذرا ذرا سی چیز پر کس حد تک لڑنے جھگڑنے کو تیار ہے۔ معمولی معمولی بات پر سب و شتم پر اتر آتا ہے۔ یوں تقویٰ کا سارا ملمع منٹوں میں اتر جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حقیقی تقویٰ کا اصل مظاہرہ کاروبار اور لین دین میں ہی ہوتا ہے۔‘‘(چھٹا خطبہ:ص۲۵۹)
ڈاکٹر محمود مرحوم، شاعر مشرق کے ہم نوا معلوم ہوتے ہیں۔ اقبالؔ نے بھی دین کی اصل روح کے بجائے رسوم و عبادات پر بے جا زور دینے کے متعلق خوب کہا ہے:
رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے
نماز وروزہ وقربانی وحج
یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے
بہرحال! ڈاکٹر غازیؒ کے فرمودہ میں سے آخری فقرے کو دیکھیے اور اس میں مندرج ’’ہی‘‘ پر غور کیجیے۔ یہ ’’بھی‘‘ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اظہارِ حقیقت نے موزوں لفظ چنا ہے اس لیے اگر کوئی تعصب یا ضد آڑے نہ آئے تو ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے ۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں کے بعد سلوک و تصوف کی غلط روی نے، عقیدہ و ضمیر کو بے عملی کی خلوت گاہوں میں تھپک تھپک کر سلا دیا۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے بجائے ’’اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی‘‘ کے نام پر بے عملی (اور بد عملی) کی راہیں کشادہ کر دی گئیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ’’اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی‘‘ اپنی اصالت میں تحرک کا باعث بنتی ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا ہی حصہ ہیں۔ بے عمل فرد ان صفات کا عملی انکار کر رہا ہوتا ہے اور نتیجے کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کی بد عملی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ: صِبْغَۃَ اللّٰہِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰہِ صِبْغَۃً وَنَحْنُ لَہُ عَابِدون (البقرۃ۲:۱۳۸) کے مفاہیم فقط اللہ ہو اللہ ہو کی رٹ لگانے کی دعوت دیتے ہیں یا سماجی معاشی و فکری فعالیت پر اکساتے ہیں؟ اقبالؔ نے کتنا درست کہا تھا کہ:
کمالِ ترک نہیں آب وگل سے مہجوری
کمالِ ترک ہے تسخیر خاکی ونوری!
ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ اوراحادیث کے دفاتر کے دفاتر اسی نوع کی غلط فہمیوں کی نہ صرف تصحیح و درستی کرتے ہیں بلکہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے صراطِ مستقیم پر گامزن کرتے ہیں۔ ڈاکٹرمحمود غازی ؒ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلاف اس مسئلے کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے:
’’ امام محمد بن حسن شیبانیؒ جو فقہ حنفی کے مدون اول ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس زمانے میں یعنی دوسری تیسری صدی ہجری میں محدثین کرام زہد اور رقاق کے موضوعات پر کثرت سے کتابیں تصنیف فرمایا کرتے تھے۔ یعنی احادیث کے مجموعے یا ان ہدایات کے مجموعے جو انسان کے دل میں دنیا سے استغنا پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، دل میں نرمی پیدا کریں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ امام محمد ؒ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ امام محمدؒ نے جواب دیا، میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے۔ یعنی جب کتاب البیوع میں بیان کردہ حلال و حرام کے احکام پر انسان مسلسل عمل کرے گا تو لازماًتدین پیدا ہو گا۔ جب تدین پیدا ہو گا تو حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو گی۔ جہاں حرام سے اجتناب کا جذبہ پیدا ہوگا، وہاں مشتبہات سے اجتناب کا جذبہ بھی پیدا ہو گا، اس لیے زہد خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص احکامِ حلال و حرام کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے زہد و استغنا کے سارے دعوے رکھے رہ جائیں گے۔ اس لیے اکل حلال کا گہرا تعلق صدق مقال سے ہے اور صدق مقال اور اکلِ حلال دونوں کا گہرا تعلق زہد و استغنا سے ہے۔‘‘(چھٹا خطبہ:ص۲۶۱،۲۶۲)
مسلم تاریخ کے اس دور میں امام محمدؒ جیسے افراد کی قبولیتِ عامہ بتاتی ہے کہ مسلم سوسائٹی کا عمومی رجحان کیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علما او رفقہا کے نزدیک دین کی اصل روح کیا تھی۔ امام محمدؒ کا طرزِ عمل صراحت کرتا ہے کہ آخرت کی منزل دنیا کے راستے سے گزر کر ملتی ہے۔ بقول اقبالؔ :
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
دنیا دارالعمل ہے اور عمل کا ’’معیاری اظہار‘‘ حلا ل و حرام کی تمیز یعنی مثبت معاشی سرگرمی سے ہوتا ہے۔ ہمیں نہایت تاسف سے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج کے علما اور فقہا عمل کے ’’معیاری اظہار‘‘ کے فروغ کے بجائے تبلیغِ محض کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ دین کی کلیت و جامعیت اور اس کلیت و جامعیت میں سے اساس پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اپنے تسکین ذوق کی خاطر کلیت کی نفی کر رہے ہیں، جامعیت کا انکار کر رہے ہیں اور اساس سے بیگانہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم دینِ اسلام کی کلیت و جامعیت کی بھر پور ترجمانی کچھ یوں کرتے ہیں:
’’مسلمانوں کی خالص مذہبی زندگی میں متعدد احکام ایسے ہیں جن کا گہرا اثر مسلم معاشرہ پر پڑتا ہے۔ کفارات، زکوٰۃ، صدقاتِ واجبہ وغیرہ جیسے احکام اس کی مثال ہیں۔ ان سب کے واضح اور نمایاں معاشی نتائج نکلتے ہیں۔ وقف ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف ایک معاشرتی اور معاشی ادارہ بھی ہے۔ یہاں تک کہ اسلامی قوانین میں بعض ایسے احکام بھی پائے جاتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد کے نتیجہ میں خالص فوجداری معاملات کے بھی جہاں معاشی اثرات نکلتے ہیں، وہاں ان کی مذہبی جہتیں بھی ہیں۔ چنانچہ دیت، قتلِ عمد کا کفارہ وغیرہ اگرچہ خالص فوجداری معاملات ہیں لیکن کفارہ جب ادا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ غریبوں کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے قواعد و ضوابط ہوں گے، ان قواعد و ضوابط کا گہرا تعلق اسلام کے فوجداری قانون سے بھی ہو گا۔ اسلام کے عبادات کے احکام سے بھی ہو گا اور ان احکام کی معاشی جہت بھی ہوگی۔ اس لیے اسلامی معاشیات کو ان تمام معاملات کو پیشِ نظر رکھنا پڑے گا۔‘‘(بارھواں خطبہ:ص۴۳۲)
دینِ اسلام کے تمام پہلوؤں کے داخلی ربط پر مبنی یہی جامعیت ہے جس کی وجہ سے اس دین کے معیارات دیگر نظاموں کے معیارات سے کافی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی نکتے کو موضوع سخن بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
’’ معاشی ترقی اسلامی تصور کی رو سے کیا ہے، مغربی تصور کی رو سے کیا ہے؟ اس کی شرائط اور تقاضے کیا ہیں؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟یہ بھی ایک اہم معاشی مسئلہ ہے جس پر مفکرینِ اسلام نے غور کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق معاشی اور اجتماعی وسائل کی تیاری اور استعمال، افرادِ کار کی تیاری، کسبِ حلال کا بندوبست اور مسلم معاشرے کی مادی اور تہذیبی مقاصد کی تکمیل، یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جن کو ترقی کا اسلامی تصور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ترقی کے اسلامی تصور میں صرف مادی ترقی شامل نہیں ہے۔ روحانی اخلاقی ذہنی اور تہذیبی ترقی بھی شامل ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ’’حیاۃِطیبہ‘‘ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ ایسی پاکیزہ اور ستھری زندگی جو ہر اعتبار سے پاکیزہ اور ہر اعتبار سے ستھری ہو۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ آسمان اور زمین کی برکتیں تم پر کھل جائیں گی۔ آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد تمام اخلاقی روحانی مادی اور اقتصادی برکات کا حصول ہے۔‘‘(تیسرا خطبہ:ص۱۵۹)
ڈاکٹر غازی مرحوم غالباًیہ کہنا چاہتے ہیں کہ مغرب میں ترقی کا معیار ، مربوط اور جامع نہیں ہے۔ وہاں شعبہ ہائے زندگی کی تقسیم نے ترقی کو بھی الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس لیے اہلِ مغرب کے ہاں معاشی ترقی کا سماجی ترقی، روحانی ترقی یا زندگی کے دیگر پہلوؤں کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں (کم از کم نظری اعتبار سے) معاشی ترقی، زندگی کے دیگر پہلوؤں سے بے نیاز رہ کر ترقی نہیں کہلا سکتی۔
ڈاکٹرمحمود احمد غازی مرحوم نے اسلامی اقتصاد کے ایک پوشیدہ گوشے کی نقاب کشائی کی ہے اور خوب کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:
’’بعض لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ جمالیات سے فرار دینی زندگی کا لازمی تقاضا ہے یا روحانی کمالات، ذوقِ جمال اور جمالیات کے ساتھ جمع نہیں سکتے۔ یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جو ہندوؤں میں عیسائیوں میں عام ہے کہ دنیا کے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ روحانی تقاضے انجام نہیں پا سکتے۔ یہ تفریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ یہاں تو ہدایت یہ ہے کہ ’’ان اللہ جمیل یحب الجمال‘‘، اللہ خود بھی جمیل ہے، صاحبِ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہاں جمال سے مراد محض جسمانی یا ظاہری جمال نہیں ہے بلکہ کردار کا جمال، کارکردگی کا جمال، خدمات کا جمال، اخلاق کا جمال ہے۔ ہر وہ چیز جس میں کمال اور جمال حاصل کیا جا سکتا ہو، اس میں کمال اور جمال حاصل کیا جانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہے۔ ایک دوسری جگہ زیادہ وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے: ’’من صنع منکم شیئا فلیحسنہ‘‘کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی چیز بنائے، یاد رکھیے کہ یہاں صنعت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں پوری صنعت اور انڈسٹری شامل ہے، ’’فلیحسنہ‘‘ تو اس کو بہت خوبصورت اور بہتر انداز سے مکمل کرے بہتر انداز سے بنائے۔ یہ صنعت کاروں کے لیے ایک ہدایت ہے کہ تم جو بھی صنعت تیار کرو، جو چیز بھی پیداوار کرنے کے لیے اختیار کرو، اس کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہو بناؤ۔‘‘ (پہلا خطبہ: ص ۵۱،۵۲)
ڈاکٹر صاحب نے جمال کی مجمل تشریح میں درست نہج کی نشاندہی کی ہے، لیکن ان کا جمال کو حَسن کے مترادف لینا شاید پوری طرح درست نہیں۔ جمال اپنی حقیقت میں اخلاق کے مبالغے کی ایک مستقل حالت ہے، جبکہ حَسن، عقل و بصیرت پر مبنی ایسے جاری عمل (فعلیت)کے لیے مستعمل ہے جو نگاہ میں بھی بھلا معلوم ہو۔ بہرحال! اس پر غور کیجیے کہ کوئی بنائی گئی چیز(مصنوع) اپنی ذات میں کیا بھلائی(حسنۃ) عمدگی رکھتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ وہ کسی نگاہ کو بھلی (خوبصورت) معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مصنوع سے الگ تھلگ کوئی دوسری چیز ہے جو اسے بھلی قرار دے رہی ہے۔ اس لیے حسنہ یعنی بھلائی کا تعلق حقیقت میں، خارج میں موجود دیگر عناصر سے اس مصنوع کی مطابقت میں ہے۔ یوں سمجھیے کہ چاند کو صرف اسی صورت میں بھلا قرار دیا جا سکتا ہے اگر یہ کائنات کے دیگر مظاہر کے ساتھ مطابقت میں ہو۔ جس طرح کائنات کے مظاہر الگ الگ اپنا وجود رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے درمیان مطابقت و موزونیت بھی پائی جاتی ہے جس سے وہ کائناتی نظم تشکیل پاتا ہے جو نہ صرف ہر کائناتی مظہر کو بقا بخشتا ہے بلکہ کائنات کی ناتمامی کو صدائے کن فکیون سناتا رہتا ہے، اسی طرح انسانوں کی بنائی ہوئی اشیا بھی دیگر اشیا (مادی وغیر مادی) اور کائناتی مظاہر کے ساتھ مطابقت میں ہونی چاہییں۔ آج کے انسان نے تکنیکی و صنعتی ترقی کے بل بوتے پر نت نئی اشیا کے ڈھیر ضرور لگا دیے ہیں، لیکن ان میں سے بعض اشیا سماجی، ارضی اور کائناتی موزونیت کی مطابقت میں نہیں ہیں جس سے(سماجی اور) ماحولیاتی آلودگی، گلوبل وارمنگ اور اوزون تہہ میں شگاف جیسے انتہائی سنجیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں سماجی ارضی اور کائناتی نظم بری طرح منتشر ہو رہا ہے۔ انسانوں کے مابین کشمکش بڑھ رہی ہے، موسموں میں تغیر رونما ہو رہا ہے، زلزلے اور سیلاب آئے دن تباہی مچاتے رہتے ہیں۔ اس سارے عمل کا ایک بنیادی سبب ہے اور وہ ہے ’’فلیحسنہ‘‘ کے بغیر ’’من صنع منکم شیئا‘‘ پر اندھا دھند مسلسل عمل کیے جانا جو حسنہ کے بجائے سیۂ کا لازمی نتیجہ دیتا ہے۔ اس لیے صناعی کے جوہر دکھانے والوں کو احسن الخالقین کی اتباع کرنی چاہیے جوخالقوں میں اس لیے بھی ’’احسن‘‘ہے کیونکہ اس کی کاریگری کے نمونے باہم مربوط اور ایک دوسرے کی مکمل مطابقت میں ہیں۔اس احسن نے انسان کو بھی احسن تقویم پر تخلیق کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ارضی صناعوں کو خود اپنی طرف ہی دیکھ لینا چاہیے کہ ان کا وجود فی نفسہ کتنا مربوط ہے اور خارجی اشیا سے کس حد تک موزوں ہے۔ اسی لیے اس کی تقویم احسن تقویم ہے۔ لہٰذا آج کی صنعت اور آج کی تکنیک کو یہ باور کرانے کی اشد ضرورت ہے کہ وسیع تر انسانی مفاد میں اس کا پیداواری اظہار، سماجی ارضی اور کائناتی موزونیت کی مطابقت میں ہونا چاہیے۔
موجودہ عالمی صورتِ حال کے تناظر میں اس بحث سے ایک لطیف نکتہ برآمد ہوتا ہے۔ آج بین الاقوامی تعلقات میں معاشی تعلقات کی اہمیت چونکہ بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے کوئی بھی عالمی تبدیلی ان معاشی تعلقات سے مَس کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آج کا مسلم ضمیر بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے عالمی معاشی تعلقات میں مذکورہ بحث کے مضمرات سمو دے تو اسے ایک غالب و جاری معاشی نظام میں جگہ بنانے کا موقع مل سکے گا جس کے توسط سے عالمی اصلاحی تبدیلی کی امید بندھ سکے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ معیشت کے اس پہلو میں بھی مغربیوں کو سبقت حاصل ہے۔ ان کے ہاں معیشت کی یہ جہت اتفاقاًسامنے آئی ہے، لیکن اس کی بنیاد وہی ’’تجربہ و مشاہدہ ‘‘ ہے جو ان کی تہذیبی اساس قرار پاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کی موزونیت کی تلاش کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دہریے لوگ خواہ مخواہ اتنے تکلف میں پڑے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ غیر موزوں مصنوع کی پیدا کردہ خرابیوں کو اللہ خود ہی دیکھ لے گا، اس کا نظامِ قدرت ہے وغیرہ وغیرہ۔
اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اب ہم فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم: ’’من صنع منکم شیئا فلیحسنہ‘‘ کو دنیا کے سامنے اس دعوے کے ساتھ پیش کریں کہ دیکھو! تم لوگوں نے صنعتی انقلاب کے بعد اور اس صنعت کی خرابیوں کے ظہور کے بعد غیر موزونیت سے آگاہ ہو کر موزونیت کا عمل شروع کیا ہے، لیکن دیکھو! اسلام نے چودہ سو تیس سال سے بھی پہلے عالمِ انسانیت کی اس سلسلے میں راہنمائی کی ہے۔ غور کیجیے کہ کیا ہمارے اس دعوے میں کوئی وزن ہوگا؟ اس قسم کے دعوے ہم اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں اور اہلِ علم ہمیں جاہل قرار دیتے ہوئے خاموشی سے اپنا کام کیے جاتے ہیں (خیال رہے یہاں اہلِ علم مغربیوں کو کہا جا رہا ہے)۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں کام کرنے کی رِیت کب ڈالیں گے؟ اور کب ہم بعد میں بے وزن حوالے دینے کے بجائے سبقت کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت کے مظاہر دنیا کے سامنے رکھیں گے؟ خیر! مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت مغرب میں ’’ماحول دوست معیشت‘‘ کو فروغ دیا جا رہا ہے یعنی معیشت کو ماحول کے ساتھ موزوں کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ ماحول میں سماج و اخلاق کو شامل نہیں کرتے۔ اگر آج کا مسلم ضمیر مغرب کی موزونیت کی تلاش میں سماج و اخلاق کو شامل کرا سکے تو نہ صرف اسلام کی عصری حقانیت کا ایک پہلو سامنے آئے گا بلکہ عالمِ انسانیت بھی اس کی احسان مند ہو گی۔ لیکن اس سلسلے میں ما بعدالصنعتی دنیا (post industrial world) کابے لاگ تنقیدی مطالعہ کرنا ہو گاکہ اس نے انفرادی اور سماجی موزونیت کو کس حد تک کہاں اور کیسے منتشر کیا ہے۔
دینِ اسلام کے تمام پہلوؤں کے درمیان normative relation پر ہمارے ممدوحؒ کی گہری نظر ہے۔ اسی معیاری تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے وہ ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں:
’’ اسلامی نظامِ معیشت کا ایک اہم میدان جس کا تعلق معاشی زندگی کے ساتھ ساتھ علم اور عدلیہ سے بھی رہا ہے، جس کا تعلق معاشرتی انصاف سے بھی بہت گہرا ہے، وہ اسلام کا ادارہ وقف ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جو روزِ اول سے اسلام کی تاریخ میں قائم رہا۔ سب سے پہلا وقف خود سرکارِ دوعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سب سے پہلا وقف قائم کرنے کی توفیق اور شرف سید نا عمر فاروقؓ کو حاصل ہوا۔ یہ ادارہ دینی، معاشرتی، تعلیمی، اقتصادی، تہذیبی، ثقافتی اور نیم عدالتی ادارہ رہا ہے۔ زندگی کے ان تمام پہلوؤں میں وقف کے ادارہ نے مثبت اور نئے نئے اثرات پیدا کیے ہیں۔ امام شافعیؒ کا ارشاد ہے کہ وقف اسلام اور مسلمانوں کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ .....ایک زمانہ تھا کہ بعض بڑے بڑے مسلم شہروں کی جائیداد کا بڑا حصہ اوقاف پر مشتمل ہوتا تھا، اس لیے کہ ہر صدی میں اور ہر دور میں مالکانِ جائیداد نے اپنی جائیدادیں وقف کیں۔ مثال کے طور پر استنبول اور مکہ مکرمہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان شہروں کی جائیدادوں کا غالب ترین حصہ وقف پر مشتمل تھا۔ ظاہر ہے یہ اوقاف ہر دور میں قائم کیے گئے، ہر صدی میں اصحابِ خیر لوگوں نے اپنی جائیدادیں وقف کیں۔ ......وقف کا اہم اصول یہ تھا جس سے تمام فقہا اتفاق کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد ہر دور میں ہوا ہے کہ ’’شرط الواقف کنص الشارع‘‘ کہ وقف کرنے والے کی شرائط کااور تفصیلات کا اسی طرح سے خیال رکھا جائے گا، اسی طرح سے ان کا اہتمام کیا جائے گا، ان کی تعبیر و تشریح انھی قواعد کے مطابق کی جائے گی جس طرح شریعت کی نصوص کی پابندی کی جاتی ہے اور تعبیر و تشریح کی جاتی ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں وقف کا ادارہ کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ ‘‘ (دوسرا خطبہ: ص۱۱۸،۱۱۹)
ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ وقف کی اہمیت، اس کی بابت اسلاف اور مسلم سوسائٹی کا طرزِ عمل، نیز امام شافعیؒ کا اسے اسلام اور مسلمانوں کی خصوصیات میں شمار کرنا، ہمارے آج کے عمومی رویے سے میل نہیں کھاتا۔ اب بات یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ وقف کو خیراتی ادارے کا نام دے کر اس کی مشابہت عیسائی مشنری اداروں میں ڈھونڈی جاتی ہے اور یہ کام ایسے لوگ کرتے ہیں جو اپنے تئیں دین اسلام کے مزاج سے پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ اور تو اور، ہمارے ہاں جو تھوڑے بہت وقف موجود ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جاتی۔ اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ اسلام کو لوٹے مصلے کی تنگنائے سے نکال کر اس کے حقیقی مزاج سے ہم آہنگ دینی تعبیر لوگوں کے اذہان میں بٹھائی جائے تاکہ وقف جیسے امتیازی اسلامی اداروں کا احیا ممکن ہو سکے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ وقف کا احیا عصری تقاضوں کی مطابقت میں ہونا چاہیے تاکہ مسلم معاشرہ اس کے عملی ثمرات سے بہرہ مند ہو سکے۔ لہٰذا ڈاکٹر غازی مرحوم کی اس تجویز سے اتفاق ضروری ہو جاتا ہے کہ :
’’اگر ایسے اوقاف قائم کر دیے جائیں جو لوگوں کو ذاتی ضروریات کے لیے بلا سود قرض دیا کریں تو بینکوں کا بہت سا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور عام لوگوں کی ایک حقیقی ضرورت کی تکمیل کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ یہ اوقاف حکومتِ پاکستان بھی قائم کر سکتی ہے، مختلف بنک بھی قائم کر سکتے ہیں، افراد بھی قائم کر سکتے ہیں۔ وقف کی یہ رقم سرمایہ کاری میں لگا دی جائے، اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں جو آمدنی ہو، اس آمدنی کو بھی وقف سمجھا جائے اور جس شخص کو بلا سود قرضے کی ضرورت ہو، مثلاًعلاج کے لیے شادی تعلیم حج وغیرہ کے لیے تو وہاں سے بلا سود قرضہ لے لے۔ اسی طرح بیت المال میں اس بات کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ پاکستان بیت المال الحمد للہ موجود ہے۔ یہ ادارہ پندرہ بیس سال سے کام کر رہا ہے۔ اگر بیت المال میں ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ ایک ریوالونگ فنڈ ہو، اس کو کسی کامیاب اور جائز سرمایہ کاری میں لگا دیا جائے۔ مثلاًاس کے حصص خرید لیے جائیں اور اس فنڈ کی آمدنی سے ذاتی مقاصد کے لیے لوگوں کو غیر سودی بنیادوں پر صرفی قرضے دیے جائیں تو یہ بیت المال کے مقاصد کے عین مطابق ہوگا۔ .......اگر قرضوں کی یہ اسکیم بیت المال میں شروع کر دی جائے تو بڑے پیمانے پر لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ جو بیت المال سے قرضہ لے کر حج کر آئے گا وہ زندگی بھر بیت المال کا شکر گزار رہے گا۔‘‘ (دسواں خطبہ: ص ۳۷۲، ۳۷۳)
واقعہ یہ ہے کہ وطنِ عزیز کے جس طبقے کی حمایت میں ڈاکٹر صاحب یہ تجاویز پیش کر رہے ہیں، اس طبقے کی جوانی نا گفتہ بہ معاشی حالت کی نذر ہو جاتی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس طبقے کی اکثریت زندگی کے آخری ایام میں آرام کرنے کے بجائے حج کی مشقت اٹھانے کو ترجیح دیتی ہے اور یوں ان کی زندگی بھر کی کمائی آخرت کے ذخیرے کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے ممدوحؒ کا یہ فرمانا کہ بیت المال سے قرضہ لے کر حج کرنے والا زندگی بھر بیت المال کا شکرگزار رہے گا، حقیقت بیانی نہیں ہے۔ اس بے چارے کی زندگی باقی ہی کتنی رہ جاتی ہے؟ یہاں بنیادی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض اٹھا کر حج کرنے کی ترغیب دینا کیا مقاصدِ شریعت سے مطابقت رکھتا ہے؟ پھر جس طبقے کو قرض اٹھا کر حج کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے، کیا اس کی معاشی زندگی اس سطح کی ہوتی ہے کہ وہ قرض لے کر کسی معاشی سرگرمی میں ملوث ہونے کے بجائے حج کرنے کی ٹھان لے؟ کیا اس طبقے کی معاشی حالت اور حج کے تقاضے ہم آہنگ اور باہم مربوط ہیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ وقف یا بیت المال کی آمدنی کا چند فی صد حصہ ایسے طبقے کے حج کرنے کے لیے مختص کر دیا جائے تو یہ بہتر تجویز ہوتی۔البتہ صرفی قرضوں کی تجویز کی حد تک ڈاکٹر غازیؒ سے سو فی صد اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ ایسے قرضے بلا شبہ وقت کی اشد ضرورت ہیں۔ اس قسم کی تجاویز ڈاکٹرمحمود غازی مرحوم کے زرخیز ذہن کی عکاسی کرتی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرحوم کا نقطہ نظرمجموعی طور پر واقعیت پسندانہ ہے۔ درج ذیل اقتباس ہی ملاحظہ کیجیے کہ ان کی سوچ کے اس رخ کا اس میں خوب اظہار ہو رہا ہے:
’’ بیمہ اورانشورنس کا اصل محرک شرعاًقابلِ اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات کہ اگر ایک شخص کو معاشی پریشانی کا سامنا ہو یا مالی مشکلات پیش آئیں تو دوسرے لوگ مل کر اس کی مدد کریں، یہ تصور شریعت میں پسندیدہ ہے اور شریعت کے احکام کے عین مطابق ہے۔ ایک حد تک یہ تصور اسلام میں پہلے دن سے موجود ہے۔ عاقلہ کے احکام احادیث میں تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ عاقلہ کے معنی یہی ہیں کہ کسی شخص پر اس کی کسی غلطی کے بغیر، کسی جرم کے بغیر یا محض بھول چوک سے کوئی تاوان مثلاًدیت یا ضمان عائد ہو جائے تو پوری برادری یا قبیلہ یا بستی کے لوگ مل کر اس کو ادا کریں۔ یہ تصور میثاقِ مدینہ میں بھی موجود ہے۔ جس کو اسلام کا پہلا تحریری دستور قرار دیا گیا ہے اور بعض اہلِ علم نے اس کو دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری دستور بھی قرار دیا ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ عاقلہ کا جو نظام قریش میں پہلے سے موجود تھا وہ بدستور جاری رہے گا۔ جس جس قبیلے میں عاقلہ کا جو نظام موجود تھا، وہ اسی طرح موجود رہے گا اور ہر گروہ رائج الوقت معروف طریقے اور انصاف کے مطابق اپنے مقروضوں کا قرض ادا کرتا رہے گا۔ خود قرآن مجید میں زکوٰۃ کی مدات میں ایک اہم مد غارمین کی رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو تو اس کا قرض زکوٰۃ سے ادا کر دیا جائے۔ .......فقہائے اسلام میں سب سے پہلے جس نے اس پر توجہ دی، وہ علامہ ابن عابدینؒ ہیں جو اپنے زمانے کے غالباًسب سے بڑے حنفی فقیہ تھے اور متاخرین فقہائے احناف میں ان کا بہت اونچا درجہ ہے۔ انہوں نے اس کے لیے سوکرہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ غالباًسکیورٹی کا معرب ہے۔ ..... انہوں نے اس معاملے کو غیر مشروع اور حرام قرار دیا ہے یعنی اس صورت کو جو ان کے زمانے میں یورپ میں رائج تھی، اس کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ .....وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے غور و خوض ہوتا گیا، بیمہ کاری کی عملی تفصیلات واضح ہوتی گئیں، بیمہ کے رائج الوقت قوانین سے آگاہی ہوتی گئی۔ بیمہ کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر بھی واضح ہوتا گیا اور بالآخر یہ طے ہوا کہ تعاونی بیمہ Cooperative Insurance جائز ہے۔ .....لیکن تجارتی بیمہ کے بارے میں علمائے کرام کی غالب اکثریت کا کہنا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ......بیمہ کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ جس کا ابھی تک قابلِ عمل اور شریعت کے اعتبار سے قابلِ قبول حل مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکا، وہ Re-insurance کامعاملہ ہے۔ ری انشورنس سے مراد یہ ہے کہ بڑی بڑی انشورنس کمپنیاں اپنے انشورنس کے معاملات کی بھی انشورنس کرواتی ہیں۔ یہ ری انشورنس یعنی بیمہ کا بیمہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ ابھی تک ری انشورنس کی کوئی قابلِ ذکر اور بڑی کمپنی دنیائے اسلام کے کسی ملک میں موجود نہیں ہے۔ ری انشورنس کے لیے جدید ماہرین نے ری تکافل کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ انگریزی میں تکافل اور ری تکافل کا لفظ اب عام استعمال ہونے لگا ہے۔‘‘(گیارھواں خطبہ:ص۴۲۲،۴۲۳،۴۲۴)
بظاہر بیمہ اور عاقلہ کے درمیان ایسا تعلق بنتا نظر نہیں آتا جیسا کہ ڈاکٹر غازیؒ نے بنا دیا ہے البتہ دونوں کے مقاصد پیشِ نظر رکھے جائیں تو نہ صرف ایسے تعلق کی گنجایش نکلتی ہے بلکہ بیمہ کو عاقلہ کا قائم مقام ٹھہرا کر ترویج دینے کی بھی ترغیب پیدا ہوجاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بنیادی اشکال وارد ہوتا ہے کہ ماضی میں تو عاقلہ کے فرائض قبیلہ انجام دیتا تھا جدید دور میں اس کی کیا صورت ممکن ہوسکتی ہے؟ اگر عاقلہ کی ذمہ داری ریاست یا ریاست کے زیرِ انتظام کسی ادارے کے سپرد کر دی جائے تو اس سے ایک تو قومی ریاست کے جدید تصور کو قبولیت عامہ ملتی ہے جس سے اسلام کا تصورِ ملت جو عوامی حلقوں میں کسی نہ کسی حد تک اب بھی پایا جاتا ہے، مجروح ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بفرضِ محال قومی ریاست اور تصورِ ملت میں تطبیق دے لی جاتی ہے تو پھر بھی جدید مسلم قومی ریاستوں میں کرپشن میں روزافزوں اضافہ، عاقلہ کی ذمہ داریاں ریاست کے سپرد کرنے میں مانع ہو جاتا ہے۔ اس لیے علاقائی بنیادوں (یعنی قومی ریاست) کے بجائے گروہی شناخت کے دیگر عناصر مثلاًبرادری، زبان، نسل وغیرہ، کو اگر نظری اعتبار سے بھی قبول کر لیا جائے(کہ عملاًانہیں قبولیت عامہ حاصل ہے)، تو نہ صرف ایک مصنوعی غیر فطری شناخت (یعنی قومی ریاست)جو گروہوں کے سر تھوپ دی گئی ہے (جس کی وجہ سے نہ مطلوب اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے اور نہ مطلوب مقاصد حاصل ہو پاتے ہیں) سے چھٹکارا مل سکتا ہے اور اسے اس کی فطری حدود میں پابند کیا جا سکتا ہے بلکہ گروہی شناخت کے فطری عناصر کو راہ ملنے سے حقیقی معنوں میں ایسا نظمِ اجتماعی قائم ہو سکتا ہے جس پر لوگ (یعنی متعلقین گروہ) واقعتادل و جان سے نثار ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ عاقلہ کی ذمہ داری ایسا ہی نظم اجتماعی بطریق احسن پوری کر سکتا ہے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ فی الحال(یعنی عبوری دور کے لیے) عاقلہ کی ذمہ داری ریاست کو تفویض کر کے کیا اصلاحِ احوال کی امید کی جاسکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا مصلحت کے خلاف ہو گاکہ یہ عبوری دور ہمیشہ ناتمام رہے گا۔ اس لیے عبوری دور کے لیے، ریاست کے بجائے معاشرے کے مختلف گروہوں کو یہ اختیار تفویض کر دیا جائے تو ایک تو یہ گروہ نسبتاًذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے اور دوسرا یہ کہ یہی گروہ ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے بتدریج دیگر ریاستی فرائض بھی سنبھالتے چلے جائیں گے اور اس دوران میں ان مختلف سماجی گروہوں کے درمیان باہمی انحصار (inter-dependence) پر مبنی ایسی موافقت بھی پروان چڑھے گی جس کے نتیجے میں امہ یا ملت کا تصور حقیقی معنوں میں اور عملی صورت میں رونما ہو سکے گا۔ اس وقت وطن عزیز میں مختلف سماجی گروہ برادری وغیرہ کی بنیاد پر عاقلہ سے مماثل فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً مختلف شہروں میں مختلف برادریوں نے ٹرسٹ ہسپتال اور تعلیمی ادارے قائم کر رکھے ہیں جن کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ اسی عمل کی توسیع کرتے ہوئے اگر بیمہ وغیرہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ برادری زبان وغیرہ انسانی شناخت کے فطری عوامل ہیں، اس لیے ان بنیادوں پر لوگ آپس میں انس و قربت محسوس کریں گے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی کریں گے۔ اس طرح تشکیل پانے والے نظام میں کسی برادری کے سرکردہ لوگ یعنی عاقلہ کے مدار المہام بھی اخلاقی دباؤ میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ برادری سے کٹ کر اور برادری کے مفادات سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا، کوئی قدم اٹھانا ان کے لیے عملاً ممکن نہیں ہو گا۔ اس کے برعکس اگر یہ ذمہ داری ریاست کے سپرد کر دی جائے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرد اور ریاست ایک دوسرے کو فریق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عاقلہ کا بنیادی فلسفہ یہی ہے اور اس کے احیا کا بنیادی تقاضا بھی یہی ہے کہ فرد اور عاقلہ کے درمیان کسی بھی حوالے سے کسی بھی نوعیت کے تناؤ یا کھینچا تانی کا کوئی احتمال سرے سے پایا ہی نہ جاتا ہو، بلکہ فرد اور عاقلہ ایک دوسرے سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں، موافق ہوں، موزوں ہوں۔
واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں صنعتی انقلاب کے بعد انسانوں کے مابین ایک نیا رشتہ تشکیل پایا ہے، وہ ہے مالک اور مزدور کا رشتہ۔ یہ رشتہ سماجیوں اکائیوں میں ایک نیا اضافہ ہے۔ اگر شروع میں ہی مالک اور مزدور کے تعلق کو ایک نئی سماجی اکائی کے طور پر دیکھا جاتا تو اسلام کے تصورِ عاقلہ وغیرہ کے تحت مالک اور مزدور کے معاملات بطریق احسن لازماً سلجھالیے جاتے۔ لیکن اب ٹریڈ یونینز اور لیبر یونینز، مالکان کو حریف کے طور پر دیکھتی ہیں اور مالکان بھی ان سے خائف رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو طرفہ مفاہمانہ طرزِ عمل کے بجائے مخاصمانہ انداز و اطور اختیار کیے جاتے ہیں۔ مالکان سیاست کرتے ہوئے ان یونینز کے عہدیداران کو ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور یہ عہدیداران ذاتی مفادات کی خاطر اپنی کمیونٹی کے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں مالک اور مزدور کے مابین مفاہمانہ طرزِ عمل سامنے آیا ہے، وہاں نہ صرف باہمی مخاصمت میں کمی واقع ہوئی ہے بلکہ مالک اور مزدور دونوں کو سہولت میسر آئی ہے، مثلاً سوشل سکیورٹی ہسپتال اور تعلیمی ادارے دیکھ لیجیے۔ اس لیے مالک اور مزدور کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یعنی اس نئے رشتے نے انہیں عاقلہ کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں چونکہ صنعتی انقلاب کے اثرات بہت بعد میں آئے، اس لیے یہ ممالک نسبتاً زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے کہ مغربی ممالک میں مالک اور مزدور کے تعلق کی کش مکش کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحِ احوال کی غرض سے کوئی متبادل صورت پیش کرتے اور اپنے ہاں صنعتی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس متبادل نظام کو رائج کرکے اس گھمبیر مسئلے کا حل دنیا کے سامنے پیش کر دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلم ممالک کے فکری راہنماؤں کی نظر عاقلہ جیسے اسلامی اداروں کی طرف اٹھ سکتی تھی، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ مسلمان تو کوئی متبادل نظام پیش کرنے سے قاصر رہے ، البتہ سوشلزم اور کمیونزم جیسا انتہا پسندانہ تصور قبولیتِ عامہ سے بہرہ مند ہوا، لیکن اس سے مالک اور مزدور کے مسائل بطریق احسن سلجھ نہیں سکے۔اس لیے اگر اسلام کے تصورِ عاقلہ کو اب بھی عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے تو مالک اورمزدور کے تعلق سمیت زندگی کے مختلف شعبوں میں مثبت پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ عاقلہ کا طرہ امتیاز انس و قربت ہے نہ کہ چپقلش و کش مکش۔
اگر واقعیت پسندی سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ فضا نے بھی مختلف فرقوں کو الگ الگ سماجی اکائیوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اس اندوہ ناک صورت کو بھی مثبت جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ ایک ہی فرقے سے وابستہ لوگ آپس میں انس و قربت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے احساسات کو عاقلانہ تنظیم دے دی جائے تو نہ صرف ایسے فرقہ وارانہ فروعی مسائل کا بیان کافی کم ہو جائے گا جن کا زندگی اور مقاصدِ شریعت سے دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فروعی مسائل کی اس جہت کو بھی فروغ حاصل ہو گا جو مقاصد شریعت سے پوری طرح ہم آہنگ ہو گی۔
اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی حلقوں کی طرف سے ایسے اقدامات کی بابت حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کی ہی توقع کی جاسکتی ہے کہ اہلِ مذہب کے نزدیک اس عمل سے امت کے مزید منتشر ہونے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ امت صرف تصور کی حد تک کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس کا سرے سے جسمانی وجود ہی نہیں ہے، چہ جائیکہ منتشر ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ مذہبی حلقوں کے اس طرزِ عمل سے البتہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ مثبت جہت میں منظم ہونے کے بجائے ایسے مختلف سماجی گروہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کا رخ بھی غلط اطراف میں مڑتا جا رہا ہے۔ اس طرح سماج کاری (socialization) کے جس جاری عمل سے عاقلہ کے ظہور کی عملی صورت ممکن ہو سکتی تھی، اس کی راہ میں قدم قدم پر اسپیڈ بریکر قائم ہو گئے ہیں۔ اس تشویش ناک صورتِ حال میں بھی اگر گروہی شناخت کے فطری مظاہر کو تسلیم کر لیا جائے اور علاقائی بنیاد پر قائم قومی ریاست کے بجائے ان سماجی گروہوں سے عاقلہ جیسے فرائض کی بجاآوری کی توقعات وابستہ کر لی جائیں تو اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت ہی کم عرصے میں یہ سماجی گروہ قدیم زمانے کے قبائل کے مانند عاقلہ کا بھر پور کردار ادا کریں گے۔اس سلسلے میں ہم محض اشارے کنایے میں یہ گزارش کریں گے کہ ایک امتیازی اسلامی ادارے وقف کو بھی عاقلہ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو مختلف شناختوں کے حامل صاحبِ ثروت افراد اپنے اپنے مخصوص گروہ کے لیے جائیدادیں وقف کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں معاشرتی و معاشی(نیز اخلاقی) ابتری میں خاطر خواہ حد تک کمی واقع ہوگی۔
مذکورہ بالا اقتباس کے آخر میں ڈاکٹر محمود مرحوم نے بیمہ کا بیمہ یعنی ری انشورنش یا ری تکافل کی بات کی ہے۔ ہمارے خیال میں ایسے امور میں قومی ریاست زیادہ بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو گی، لیکن ایسی قومی ریاست جو مختلف شناختوں کے حامل مختلف سماجی گروہوں کی حقیقت یعنی کثرت میں وحدت (unity in diversity) کو قبول کرتے ہوئے وحدت میں کثرت (diversity in unity ) کا واقعیت پسندانہ مظاہرہ کرے۔ اسی اصول کو مزید پھیلاتے ہوئے عالمی سطح پر اوآئی سی، رابطہ عالم اسلامی وغیرہ کے پلیٹ فارم سے بیمہ کا بیمہ کا بھی بیمہ ممکن ہو سکے گا جس کے نتیجے میں معیشتِ اسلامی کا ایک گم گشتہ باب عصری تقاضوں کی مطابقت میں بازیافت ہو گا۔
وسائل رزق اور مال و دولت کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، ڈاکٹر محمود احمد مرحوم اس پر یوں اظہارِ خیال کرتے ہیں:
’’یہ مال و دولت یہ وسائل جو اللہ نے روئے زمین پر پیدا کیے ہیں، یہ انسانی معاشرے کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے خون کی ہے۔ قرآن کریم نے مال و دولت کو قیام للناس کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ ......کوئی معاشرتی یا اجتماعی زندگی، معاشی سرگرمی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اور معاشی سرگرمی کے لیے مال و دولت کا ہونا وسائل رزق او راسبابِ پیداوار کا ہونا ناگزیر ہے۔ اس لیے اسبابِ رزق اور وسائل پیدا وار کی حیثیت قیام للناس کی ہے۔‘‘(پہلا خطبہ:ص۲۶)
واقعہ یہ ہے کہ اگر تعصب آڑے نہ آئے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کارل مارکس کی جدلیاتی مادیت (Dialectical Materialism ) کا پس منظر جدا ہے، الفاظ جدا ہیں، ورنہ قیام للناس اور اس کے درمیان کوئی آہنی پردہ (iron curtain) حائل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی درج ذیل وضاحت سے مزید صراحت ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:
’’انسان یہ سمجھ لے کہ جو مال و دولت میرے تصرف یاقبضے میں ہے، میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہوں۔ ’’المال مال اللہ‘‘ یہ سارا مال اللہ کا ہے اور میری حیثیت اس مال میں اللہ کے جانشین کی ہے۔ ’’مستخلفین فیہ‘‘ کہ تم لوگوں کواس مال میں اللہ کا جانشین بنایا گیا ہے، اس لیے یہ رویہ ’’ان نفعل فی اموالنا ما نشاء‘‘ کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ گویا جس رویے کو مغربی معاشیات کی تاریخ میں laissez faire کہا جاتا ہے، یہ رویہ اسلامی شریعت سے متعارض ہے۔ اسلامی معیشت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریگولیٹڈ معیشت کی علم بردار ہے۔‘‘ (پہلا خطبہ: ص ۳۱، ۳۲)
پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ’’المال مال اللہ‘‘ اور ’’مستخلفین فیہ‘‘ کی تشریح یک رخی کی ہے۔ سورۃ النساء، آیت۹۷ میں ’’مستضعفین فی الارض‘‘ (oppressed in earth) جیسے جواز پر اللہ رب العزت کی گرفت: ’’ فَأُوْلَئِکَ مَأْوَاہُمْ جَہَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیْراً‘‘ کتنی سخت ہے، اس کو دھیان میں رکھیے اور سورۃ الحدید کی آیت۷ میں مذکور ’’مستخلفین فیہ‘‘ (in which as deputies) پر دوبارہ غور کیجیے۔ کیا اس کا یہی مطلب نہیں کہ جب مال کسی بشر کی ملک ہی نہیں بلکہ بشر مستخلفین (deputies) ہیں تو پھر وہ کیونکر خود کو پستی میں گرا کر مستضعفین (oppressed) کی سطح پر قانع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مستضعفین کا جدوجہد کر کے خود کو مستخلفین کی صف میں شامل کرانا (یعنی یکساں حقوق و یکساں نیابت کا دعویٰ کرنا) شارع کا منشا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے مسلمہ حقیقت (settled fact) قراردے رہے ہیں کہ سبھی انسان مستخلفین ہیں اور مستضعفین سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں، مسلم ممالک میں اور وطن عزیز میں کتنے فی صد لوگ ہیں جو مستخلفین کی حیثیت میں جی رہے ہیں اور کتنے فی صد لوگ مستضعفین کی پست سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، یہ جاننے کے لیے کیا اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کی ضرورت ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے نوعِ انسانی کو اصولاًاور مقصوداً مستخلفین کے مقام سے نوازا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے سورۃ الحدید جیسے بیانات یاددہانی اور تنبیہ سے عبارت ہیں کہ کہیں نوعِ انسانی کا کوئی طبقہ اپنے تئیں مستخلفین کی سطح سے بلند ہوکر قارون کی طرح مال و دولت کا مالک بن بیٹھے اور دیگر طبقات کو مستضعفین کی انتہائی پست و حقیر سطح پر لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی طاقت ور ہونا اور انتہائی کم زور پسا ہوا ہونا، قرآن کے مطابق دو انتہائیں ہیں اور ان کے درمیان نقطہ اعتدال مستخلفین ہونا ہے۔ غالباًڈاکٹر غازی مرحوم مستضعفین کو قارونی طبقہ کے خلاف بغاوت پر اکسا کر قرآنی نقطہ اعتدال (جسے وہ خود قیام للناس کہتے ہیں) کے ابلاغ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، اسی لیے مستخلفین کو امر واقعی کے انداز میں لے رہے ہیں۔ خیر! یہ کوئی نئی بات نہیں،تاریخ بتاتی ہے کہ (شاہ ولی اللہؒ اور کارل مارکس جیسے افراد کے استثنا کے ساتھ) علما اور سکالرز کی اکثریت کا یہی شیوہ رہا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ laissez faire سے مراد معیشت کا ریاستی کنٹرول سے حتی الامکان آزاد ہونا ہے۔ اگر ’’الاصل فی المعاملات الاباحۃ‘‘ کے اصول کے تناظر میں دیکھا جائے تو laissez faire کو اسلامی شریعت سے متعارض قرار دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بازار کے معاملات کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے ریگولیٹڈ اکانومی کو اسلامی قرار دینا خاصا مشکل ہے کہ اس میں بازار کے معاملات میں(ریاست وغیرہ کی طرف سے) غیر فطری مداخلت کا احتمال موجود رہتا ہے۔ اسلامی معیشت کے بارے میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مائیکرو لیول پر اس میں laissez faire کی گنجایش موجود ہے اور میکرو لیول پر ریگولیشن کی، یعنی ریاست ضرورت پڑنے پر فطری مداخلت کی حد تک محدود رہے۔ سیدنا عثمان غنیؓ کے درج ذیل طرزِ عمل سے بخوبی اندازہ ہو تا ہے کہ فرد کی آزادی اور ریاست کی حاکمیت کے درمیان خط تفریق کہاں کھینچا جاناچاہیے:
’’ حضرت عثمان غنیؓ کے زمانے سے یہ روایت چلی آرہی ہے کہ اموالِ ظاہرہ کی زکوٰۃ ریاست وصول کرتی تھی اور اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ افراد خود دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنیؓ کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بہت سے معاملات میں ایسے فیصلے کیے جن کے بہت دور رس اثرات ظاہر ہوئے اور اگر وہ یہ فیصلے نہ فرماتے تو آج بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے ہوتے۔ چنانچہ اموالِ ظاہرہ اور اموالِ باطنہ کی تقسیم بھی ان اہم معاملات میں سے ایک ہے۔ سیدنا عثمان غنیؓ نے یہ محسوس فرمایا کہ ہو سکتا ہے آئندہ چل کر کچھ لوگ اپنے اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ دینے میں تامل کریں۔ محصلِ زکوٰۃ اصرار کرے کہ ان کے پاس مال ہے، وہ اصرار کریں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے اور نوبت تلاشی اور گرفتاری تک پہنچے تو یہ سرکاری کارندوں کو ایک ایسا ہتھیار دینے کے مترادف ہو گا جس سے کام لے کر سرکاری کارندے ہر شخص کی شخصی زندگی میں بے جا مداخلت کر سکتے ہیں۔ یوں تجسس کا ایک ایسا مکروہ عمل عام ہو جائے گا جس کے نتیجے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہوں گی۔ شریعت نے تجسس سے منع کیا ہے۔ عامۃ الناس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس لیے یہ توقع کرنی چاہیے کہ عامۃ الناس اپنے اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ خود ادا کر دیں گے اور اموالِ ظاہرہ کی زکوٰۃ ریاست وصول کرے گی۔‘‘ (پانچواں خطبہ: ص ۲۱۴، ۲۱۵)
بہرحال! فرد کی معاشی آزادی اور ریاستی مداخلت کی حدود خاصا نازک مسئلہ ہے۔ یہ تناؤ اور کھینچا تانی کی دو مستقل حالتیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی بہت واضح برتری، معاشی واخلاقی توازن کے بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یہ ایک زاویہ نگاہ ہے اسے دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمود مرحوم فرماتے ہیں کہ:
’’ یہ بات کہ تجارت میں حصہ لینا فی نفسہ نیکی کا کام ہے اور خدمتِ خلق ہے، یہ متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروقؓ نے فرمایا اور یہ روایت موطا امام مالکؒ میں موجود ہے کہ جو شخص گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر ہماری منڈیوں میں باہر سے مال لے کر آتا ہے اور اس کو فروخت کرتا ہے تو وہ عمر کا مہمان ہوگا ، یعنی سرکاری مہمان ہوگا۔ ہماری مہمانی کے دوران جس طرح چاہے، اپنا سودا فروخت کرے اور جتنا چاہے، فروخت کرے اور جتناچاہے، فروخت نہ کرے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تاجروں کو سہولتیں فراہم کرے اور ان سہولتوں کو فراہم کرنے میں سرکاری وسائل بھی خرچ کرے۔ ‘‘(چھٹا خطبہ: ص ۲۳۶، ۲۳۷)
نیکی کے جس تصور کی تبلیغ ڈاکٹر غازی مرحوم کر رہے ہیں ، اس کا تصور بھی ہمارے ہاں محال ہے۔ لیکن فاروقِ اعظمؓ کا عمل صراحت کر رہا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان نیکی کے حقیقی تصور سے نہ صرف پوری طرح آگاہ تھے بلکہ عملاًاس پر کاربند تھے۔ تاجر کو سرکاری مہمان بنانے والی بات پر ذرا غور تو کیجیے کہ مومنین کی ہےئت اجتماعی(خلیفہ یا خلافت) اس کی مہمان نوازی کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ خلافت کے ذریعے سے مومنین اور اسلام کے مجموعی فکر و عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ اس اظہار کی نوعیت پر دوبارہ غور تو کیجیے اور اپنے ہاں رائج دین کے فرسودہ تصور پر ماتم کیجیے۔ اس اقتباس کا یہ بیان کہ ’’جس طرح چاہے جتنا چاہے اور جتنا نہ چاہے‘‘ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ڈاکٹر مرحوم نے بنا دیاہے۔ اس کی بابت ہماری رائے یہ ہے کہ سیدنا عمرفاروقؓ کے اس بیان کو ان کے دیگرمعاشی سرگرمیوں سے متعلق بیانات اور شریعت کے منشا کے ساتھ ملا کر سمجھنا چاہیے۔
یہاں موقع کی مناسبت سے غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ چند اصولی نکات پر بحث چھیڑی جائے تاکہ فرد کی آزادی اور ریاستی مداخلت کے حوالے سے دوسرا زاویہ نگاہ سامنے آ سکے۔ دیکھا جائے تو فرد کی آزادی کے دو پہلو ہیں: مثبت اور منفی۔ مثبت سے مراد فرد کو ایسی سہولیات کی فراہمی ہے جن کے بغیر اس کی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار نہیں ہو سکتا اور منفی سے مراد فرد کی خود غرضی وغیرہ کی تہذیب کے لیے اس پر پابندیاں عاید کیا جانا ہے کہ اس کی خود غرضی سے دوسرے افراد کی آزادی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں(اور اس سے اس کی اپنی آزادی بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہے)۔ اسی بات کو پلٹا کر دیکھا جائے تو ریاستی مداخلت کے بھی دو پہلو سامنے آتے ہیں، مثبت اور منفی۔ فرد کی صلاحیتوں کے بہتر اظہار کی غرض سے اگر ریاست مداخلت کرتے ہوئے سہولتیں فراہم کرتی ہے تواسے مثبت مداخلت کا ہی نام دیا جا سکتا ہے اور فرد کی خود غرضی وغیرہ کی تہذیب کے لیے اگر اس پر پابندیاں عائد کرتی ہے تو اسے منفی مداخلت کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ دیگر افراد یعنی سوسائٹی کی آزادی کو لاحق خطرات دور کرنے کی غرض سے منفی مداخلت کی جاتی ہے، اس لیے اسے منفی مداخلت کا عنوان دینا شاید مناسب نہ ہوگا، بلکہ یہ مثبت مداخلت سے بڑھ کر دوہری مثبت مداخلت ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مباک کہ محمد کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، اس دوہری مثبت مداخلت کی بہترین مثال ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اسلامی احکامات کا نفاذ ہمیشہ مثبت مداخلت کے لیے ہوتا ہے، چاہے اکہری مثبت مداخلت ہو چاہے دہری مثبت مداخلت ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی احکامات کا نفاذ، لفظوں کی خاطر کسی انسان کی جان لینا نہیں ہے یا لفظوں کی خاطر کسی انسان کے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے وغیرہ، بلکہ اصلاً ومقصوداً مفادِ عامہ کے تحفظ یا کلی مصلحت کی غرض سے ان احکامات کی تنفیذ کی جاتی ہے، وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ انسان الفاظ سے کہیں زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ بخاری کی اس روایت پر غور کیجیے اور بتائیے کہ کیا اس میں اور ریاست کی مذکورہ دوہری مثبت مداخلت میں مماثلت نہیں پائی جاتی؟ اس روایت سے سے ہمارے موقف کی تنقیح ہو جاتی ہے:
’’اللہ کی کھینچی ہوئی حدود کا پاس رکھنے والے اور ان سے تجاوز کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے باہم شریک ہو کر ایک کشتی حاصل کی۔ کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ لوگوں کو نیچے کا۔ جو لوگ نیچے کے حصے میں رہتے تھے، ان کو پانی پینے کے لیے اوپر والوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا اچھا ہوتا اگر ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں۔ اگر لوگ ان کو ان کا ارادہ پورا کرنے دیں تو خود بھی ہلاک ہوں اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ بھی بچ جائیں اور سب کے سب نجات پائیں۔‘‘ (بخاری، رقم ۲۳۶۱)
المختصر! کلی مصلحت یا مفادِ عامہ (public interest) کے تحفظ کے اس اصول کا پورا پورا لحاظ اسلامی معاشی احکامات کو روبہ عمل لاتے ہوئے بھی رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سیدناعمرفاروقؓ مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ریاستی مداخلت کی سنگل مثبت جہت کا اظہار کرتے ہیں اور مفادِ عامہ (public interest) کے تحفظ کے اصول کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔
اسلامی معیشت کی رو سے جدید بینکاری میں ربا(سود) ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ربا کے بارے میں وہ ایک اصولی بات سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
’’ ربا کے باب میں ایک بنیادی اور اہم بات یاد رکھنی چاہیے، نہ صرف ربا کے باب میں بلکہ یہ حکم شریعت کے تمام معاملات اور لین دین سے متعلق ہر قسم کے کاروبار میں دیا گیا ہے: ’’العبرۃ با لمضمون والجوہر ولیس بالصورۃ والمظھر‘‘ کہ کسی کاروبار یا تجارت یا لین دین کے حلال و حرام ہونے میں اصل اعتبار اس کے مندرجات اور اس کے مضمون کا ہے، اس کی ظاہری صورت یا عنوان کا نہیں ہے۔‘‘(ساتواں خطبہ: ص ۲۷۴)
ہمارے خیال میں غلامی کے مسئلے میں بھی ظاہری صورت یا عنوان کے بجائے مندرجات حقیقت اور ماہیت کو لیا جائے تو معلوم ہوجاتا ہے کہ جدید دور کی پیچیدگی نے ربا کے مانند غلامی کو بھی ملفوف کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ربا کے بارے میں تو پھر بھی بات اٹھتی رہتی ہے، لیکن غلامی کے بارے میں علما وفقہا مکمل خاموش ہیں اور اس کے نت نئے عنوانات کو اس کے مندرجات کی بنیاد پر ہدفِ تنقید نہیں بناتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جدید دور میں معاشی مسئلے کا حقیقی حل صرف ربا کے خاتمے سے ممکن نہیں ہے بلکہ ربا کا بھی مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ غلامی کے عنوان کے خاتمے سے قطع نظر اس کے مندرجات کی حقیقت کو تسلیم کرکے اصلاحِ احوال کی کوشش نہ کی جائے۔ خیر! یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ ڈاکٹر محمود احمد مرحوم ربا(سود) سے متعلق بات بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:
’’ربا کی حرمت شریعت کے بہت سے احکام کی طرح بالتدریج نازل ہوئی ہے۔ شریعت کا یہ مزاج رہا ہے کہ بہت سی اصلاحات میں بہت سے اہم معاملات میں احکام کے نزول میں تدریج سے کام لیا گیا ہے۔ اگر کوئی عادت خاص طور پر عادتِ قبیحہ لوگوں میں بہت جاگزین تھی تو اس کو بیک وقت ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس تدریج کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کوئی غیر عملی نظام نہیں ہے۔ شریعت کی بنیاد محض جذبات و احساسات یا عواطف پر نہیں ہے۔ اگرچہ جذبات و احساسات و عواطف کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے اور شریعت بھی اس اہمیت کا احساس و ادراک رکھتی ہے، لیکن انسانی معاملات میں حقائق پر نظر رکھنا واقعات اور انسانی زندگی کی نفسیات کو پیشِ نظر رکھنا، یہ شریعت کے اہم امتیازی اوصاف میں سے ہے۔ ان اہم امتیازی اوصاف میں تدریج کا طریقہ کار بھی ہے۔‘‘(ساتواں خطبہ:ص۲۷۵)
تدریج کے اصول کی وضاحت ڈاکٹر صاحب کے ذمہ تھی کہ آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کا عمومی جواب ’’نہیں‘‘ میں ملتا ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب اس نفی میں شریک معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال! ڈاکٹر غازی مرحوم مضاربہ کو سود کی متبادل اساس قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلامی بینکاری مضاربہ کی بنیاد پر کھڑی کی جا سکتی ہے، کہتے ہیں کہ:
’’ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں نبوت سے بہت پہلے مضاربہ کی بنیاد پر کاروبار کا آغاز فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریؓ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ مضاربہ ہی کی ایک شکل تھی۔ بعد میں بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرامؓ نے مضاربہ کی بنیاد پر کاروبار کیے۔ ....... مضاربہ کی بنیادی روح یہ ہے کہ سرمایہ دار یا جس شخص کے پاس سرمایہ یا سامانِ تجارت ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تجارت اور کاروبار میں بھی مہارت رکھتا ہو۔ دوسری طرف جو شخص تجارت اور کاروبار کے گروں سے واقف ہے اور تجارت کا تجربہ رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سرمایہ بھی رکھتا ہو۔ اس لیے ان دونوں کے وسائل سے بیک وقت فائدہ اٹھانے کے لیے مضاربہ کا طریقِ کار دنیا میں بہت پہلے سے رائج ہے۔ ...... بیسویں صدی کے وسط میں جب اسلامی بینکاری پر گفتگو اور بحث و مباحثے کا آغاز ہوا تو اہلِ علم کی نظر سب سے پہلے مضاربہ پر پڑی، اس لیے کہ مضاربہ وہ طریقِ کار ہے جس کو بہت آسانی کے ساتھ جدید بینکاری کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو حضرات بینکوں میں اپنی رقوم رکھتے ہیں، ان کی حیثیت رب المال کی قرار دی جا سکتی ہے۔ گویا وہ رب المال ہیں اور وہ اپنا سرمایہ کاروبار اور تجارت کے لیے دے رہے ہیں۔ بنک کی حیثیت اس مضارب کی ہو گی جو اپنے سرمایے کو آگے مضاربہ پر دے دیتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس عنوان کے تحت اس موضوع پر بحث ہوتی ہے: ’’باب المضارب یضارب‘‘۔ مضارب اگر آگے مضاربہ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے اور رب المال کی اجازت سے کچھ شرائط کے تحت وہ آگے دوسرے کاروباریوں سے مضاربہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ بنک ان تمام رقوم کو لے کر کچھ رقوم کو تو خود کاروبار میں لگاتا ہے اور بقیہ رقوم کو وہ آگے کاروبار کے لیے تجارت کرنے والوں کو دے دیتا ہے۔ یہ entrepreneur جو بنک سے سرمایہ لے کر تجارت کرتے ہیں، صنعت لگاتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرتے ہیں، یہی دراصل مضارب ہیں۔ بنک کی حیثیت درمیانی کارندے کی ہے۔ یہاں بنک کی دو حیثیتیں ہیں۔ اصل رقم دینے والوں کے لیے اس کی حیثیت مضارب کی ہے اور اصل مضارب کے مقابلے میں اس کی حیثیت رب المال کی ہے۔ اس عمل کو اگر شریعت کے احکام کے مطابق انجام دیا جائے تو یہ جدید بینکاری کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے موزوں ترین اور مفید ترین طریقِ کار ہے۔‘‘(آٹھواں خطبہ:ص۳۱۴،۳۱۵)
ڈاکٹر صاحب کی تجویز بلاشبہ کارآمد ہے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسلامی طریقوں، اصولوں اورمقاصد سے مماثلت رکھنے والے مغربی یا غیر اسلامی بینکوں کے طریق ہائے کار سے سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے:
’’ ایک اہم بات یہ ہے کہ خود مغربی دنیا میں مضاربہ سے ملتا جلتا ایک طریقِ کار رائج ہے جس پر وہاں بہت کامیابی سے عمل ہورہا ہے۔ یہ طریقِ کار venture capital کہلاتا ہے۔ وینچر کیپیٹل کی روح بھی یہی ہے کہ سرمایہ فراہم کرنے والا ایک شخص ہو ، جس کو وہاں خاموش شریک یعنی sleeping partner کہا جاتا ہے۔ وہ براہ راست کاروبار میں حصہ نہیں لیتا ۔ دوسری طرف کاروبار کرنے والا شخص ہوتا ہے جو اصل کاروبار کرتا ہے، یہی دراصل مضارب ہے۔ وینچر کیپیٹل کو بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی بڑی تبدیلی کے مضاربہ کے احکام کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ ......ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مضاربہ پر کسی کو مال دیں گے تو وہ لازماً کاروبار میں نقصان ظاہر کرے گااور یہ دعویٰ کرے گا کہ مضاربہ میں کوئی نفع نہیں ہوا۔ لہٰذا جو گھر بیٹھا شریک (sleeping partner) ہے اس کو نقصان ہی نقصان ہو گا۔ یہ اعتراض بلاشبہ وزن رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارا تجربہ اس طرح کی سرمایہ کاری کے بارے میں خوش آئند نہیں رہا۔ ماضی میں فائنانس کمپنیوں کے حالات اور کارکردگی سے ہم سب واقف ہیں۔ تاج کمپنی جیسے ادارے میں جو مسائل پیدا ہوئے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس لیے بعض لوگ مضاربہ پر عمل درآمد کے بارے میں واقعتا اس لیے تامل کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کے اعتماد پر بھروسہ کر کے ان کو بھاری رقمیں سرمایہ کاری کے لیے دے دی جائیں تو اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ وہ واقعتا اصل حسابات مالکانِ سرمایہ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو ان کا جائز حق ادا کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر وینچر کیپیٹل کے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مغربی دنیا میں اس پر کیسے عمل ہو رہا ہے، وہاں کے تجربات اور طریقہ کار سے استفادہ کیا جائے تو مضاربہ کو درپیش بہت سی مشکلات پر قابو پایا جاسکتاہے۔‘‘(آٹھواں خطبہ:ص۳۱۶،۳۱۷)
مغربی نظام کی افادیت و کامیابی کو ڈاکٹر غازی مرحوم صحیح تناظرمیں نہیں دیکھ پا رہے۔ مغربی بینکاری میں رائج وینچر کیپٹیل کی کامیابی کا راز محض قواعد و ضوابط کی طلسم کاری نہیں ہے۔ وہاں قواعد و ضوابط حقیقت میں امدادی و اضافی حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ جب بھی مغربی سوسائٹی کے معاشی مقاصد اور ان قواعد و ضوابط میں مطابقت کم ہونی شروع ہوتی ہے تو وہ لوگ قواعد پر مقاصد کو ترجیح دیتے ہوئے فوراًسے پہلے مقاصد سے ہم آہنگ قاعدی تبدیلی کر لیتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل مغرب بحیثیت مجموعی، اپنے معاشی مقاصد سے پوری طرح متفق اور باخبر ہیں۔ اس اتفاق و باخبری نے ان میں ایک خاص اخلاقی حِس پیدا کر رکھی ہے جس کا تعلق معاملات و معاشیات سے ہے۔ اسے ہم (business ethics) کا نام دے سکتے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ اس حِس کی غیر موجودگی یا اس کا خوابیدہ ہونا ہے۔ اس لیے یہ محض خام خیالی ہے کہ وینچر کیپٹیل میں رائج قواعد سے استفادہ کر کے مضاربہ کو درپیش مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جو بات مغربیوں سے سیکھنے کی ہے ڈاکٹر غازیؒ سمیت ہم میں سے اکثر لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہیں۔ ہم کسی طور یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ مغربی تہذیب صرف مادی اعتبار سے ترقی یافتہ نہیں ہے بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی برتر و بالادست ہے۔ یعنی ہم صرف مادی ترقی میں پیچھے نہیں ہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی ناگفتہ بہ حالت میں ہیں۔ اگرچہ اپنے تئیں ہم یہ دعویٰ کرنے سے بالکل نہیں چوکتے کہ مغربیوں کو اخلاقیات کا درس ہم سے ضرور لینا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اس قسم کے دعوے حقیقت سے فرار کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہی قوم دنیا کی راہنمائی کے منصب پر فائز ہوتی ہے جو اخلاقی لحاظ سے بھی نسبتاًبہتر حالت پر قائم ہو۔ اس لیے ہمیں معاشی ترقی میں مطلوب اخلاقیات (business ethics) کو رواج دینے کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ مغربی طرزکے ظاہری قواعد و ضوابط کی اندھا دھند پیروی کی۔ بہرحال! سود کی متبادل اساس کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ:
’’مشارکہ یا شرکت سے مراد ہر وہ کاروبار ہے جو دو یا دو سے زائد افراد مل کر کریں۔ آج کل کی اصطلاحات کی رو سے پارٹنر شپ، جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور کارپوریٹ فائنانسنگ کی ساری قسمیں، یہ سب مشارکہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ......فقہائے اسلام جس زمانے میں مشارکہ کے احکام مرتب فرما رہے تھے، اس زمانے میں مشارکہ کی جو جو شکلیں رائج تھیں، ان کا انہوں نے جائزہ لیا اور شریعت کے قواعد کی روشنی میں ان کے احکام مرتب کر دیے۔ اس زمانے میں شرکتِ عنان، شرکتِ مفاوضہ وغیرہ قسم کی شراکتیں رائج تھیں۔ بعض علما کا خیال ہے کہ آج کل کارپوریٹ فائنانسنگ کے نظام کے تحت جو کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، ان کی نوعیت شرکتِ عنان سے بہت مشابہ ہے۔ اس لیے ان علما کے خیال میں شرکتِ عنان کے احکام کے تحت کمپنیوں کے نظام کو بہت آسانی کے ساتھ شریعت کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ ......بالفرض اگر شرکتِ عنان کی تفصیلات کسی کمپنی کے طریقِ کار پر پوری نہیں اترتیں تو بھی اس کمپنی کے کاروبار کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شرکتِ عنان کے سو فی صد مطابق ہو۔ اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ اس کے قواعد و ضوابط اور طریقِ کار میں کوئی چیز شریعت کے قواعد اور احکام سے متعارض نہیں ہے تو وہ جائز ہے، چاہے اس کو شرکتِ عنان کہا جا سکے یا نہ کہا جا سکے۔ یہی کیفیت مشارکہ کی دوسری قسموں کی ہے۔ .......علامہ عزالدین بن عبدالسلام نے اپنی انتہائی فاضلانہ کتاب ’’قواعد الاحکام فی مصالح الانام‘‘ میں بیان کیا ہے ’’کل تصرف تقاعد دون تحصیل مقصودہ فھو باطل‘‘ کہ ہر وہ تصرف یا سرگرمی جس سے اس کا اصل مقصود پورا نہ ہو وہ باطل ہے۔ لہٰذا مشارکہ متناقصہ ہو، مشارکہ منتہیہ بالتملیک ہو یا اور نئی شکلیں ہوں، اگر ان کے نتیجے میں شریعت کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، اگر ان کے نتیجے میں عامۃ الناس نفع نقصان کے تحت کاروبار میں آزادانہ شریک ہو رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی طریقِ کار میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تو پھر یہ سب جائز ہیں۔ لیکن اگر یہ مقاصد ان سے پورے نہیں ہو رہے تو محض عربی میں نام رکھ لینے سے کوئی طریقِ کار جائز نہیں قرار دیا جا سکے گا۔‘‘ (آٹھواں خطبہ: ص ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰)
ہمارے ممدوحؒ نے سود خوری سے جنم لینے والی برائیوں مثلاً بزدلی، سستی، کاہلی وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ سود خور اپنے سرمایے کاغیر فطری تحفظ کرتے کرتے over-protection کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایسی جملہ صفات جو تازہ خون کے مانند جسم کو توانا رکھتی ہیں، آہستہ آہستہ اس سود خور فرد و قوم سے رخصت ہو جاتی ہیں۔مثال کے طور پر جرات، اقدام اور حوصلہ ، صحت مند زندگی کی لازمی صفات ہیں۔ ان اوصاف سے مزین انسان مثالی طرزِ عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ معاشی زندگی میں ایسے مثالی طرزِ عمل کی بابت ڈاکٹر غازی مرحوم کہتے ہیں کہ:
’’ دوسری بات جو شریعت کے احکام سے واضح طور پر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تاجر اور کاروبار کرنے والے میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ پہل کرسکے اور اقدام کر سکے یعنی کوئی جرات مندانہ قدم اٹھا سکے۔ یہ کامیابی اور ترقی کی ایک اہم شرط ہے۔ زندگی کے کسی بھی پہلو میں واقعہ یہ ہے کہ پہل اورا قدام کا حوصلہ رکھے بغیر کامیابی اور ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ ربا اور سود خوری سے یہ جذبہ ختم ہوجاتا ہے۔ گھر بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے یہ کوشش کی ہے اور جا بجا ایسے احکام دیے ہیں جن کے نتیجے میں ہر جائزروزی کمانے والا محنت، پہل اور اقدام سے کام لے۔ گھر بیٹھ کر کھانے کا عادی نہ ہو۔ اس لیے کہ گھر بیٹھ کر کھانے سے تجارتی سرگرمی بھی کم زور ہو جاتی ہے اور پہل اور اقدام کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔‘‘(چھٹا خطبہ:ص۲۴۱)
ہماری ناقص رائے میں گھر بیٹھ کر کھانے سے پہل اور اقدام کا جذبہ ختم نہیں ہوتا بلکہ غلط رخ موڑ لیتا ہے جس سے کئی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ بات اب تقریباًمسلمات میں سے ہے کہ انسانی جذبات کی تہذیب کی جا سکتی ہے، لیکن انہیں مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھیے جیسے مادہ ختم نہیں ہوتا بلکہ شکلیں بدلتا رہتا ہے، اسی طرح انسانی جذبات بھی اظہار کے نت نئے پیرایے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں درست سمت میں گامزن (channelize) نہ کیا جا سکے تو کسی چاتر بہروپیے کے مانند یہ روپ بدلتے رہتے ہیں۔ جب بدلے ہوئے روپ میں ان کا اظہار ہوتا ہے تو ظاہر بین سمجھتے ہیں کہ اصل جذبہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، حالانکہ یہ وہی اصل جذبہ ہوتا ہے جو مناسب راستہ نہ ملنے کی وجہ سے سی آئی ڈی کو چکمہ دے کر کہیں نہ کہیں کارروائی ڈال رہا ہوتا ہے۔ ربا (سود) کے معاملے میں یہ نہایت ہی اہم نکتہ ہے کہ اس سے انسانی فعلیت کی ایک خصوصیت ’’پہل‘‘ کا اظہار نامناسب بلکہ اکثر اوقات شرم ناک انداز میں اور غیر موزوں مقامات پر ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ اسے درست سمت میسر نہ ہونے کی وجہ سے معاشی سرگرمی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے غلط رخ لینے سے کئی قسم کے نفسیاتی و اخلاقی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا انجام سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔
مسلکی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کے یہاں عصبیت نہیں پائی جاتی۔ ان کا رجحان ’’امتزاجی مسلک‘‘ کی جانب ہے جس کا اظہار انہوں نے بغیر لگی لپٹی رکھے کافی کھل کر کیا ہے۔ مثلاًفرماتے ہیں کہ:
’’بینکوں کو شکایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی شخص بینکوں سے رقم لینے آتا ہے تو بڑی موثر اور متاثر کن قسم کی رپورٹ لے کر آتا ہے۔ .......چند سال گل چھرے اڑانے کے بعد آتا ہے، بینکوں کو درخواست دیتا ہے کہ میری صنعت تو نہیں چلی، میری تجارت میں تو گھاٹا ہو گیا۔ اس سارے عمل کی حیثیت چونکہ ایک وعدے کی ہے اور فقہ حنفی کی رو سے کوئی وعدہ عدالتی اور قانونی طور پر واجب العمل نہیں ہوتا، اس لیے اس فزیبلٹی رپورٹ feasibility report میں کیے گئے وعدوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل بعض عرب ممالک میں اہلِ علم نے تجویز کیا ہے۔ انہوں نے فقہ مالکی سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے وعدے کی بنیاد پر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جو وہ نہ کرتا اگر اس سے یہ وعدہ نہ کیا جاتا، اور وعدہ بعد میں جھوٹا ثابت ہو تو وعدہ کرنے والا اس نقصان کی تلافی کا پابند ہے۔ اس لیے عرب ملکوں میں عام طور پر رائے یہ ہے کہ فزیبلٹی رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس کو حتمی کمٹمنٹ سمجھا جائے گا اور اس کی قانونی اور عدالتی پابندی لازمی ہو گی، الا یہ کہ فریق عامل یعنی entrepreneur یہ ثابت کرے کہ جن اسباب سے وہ تجارت یا صنعت کامیاب نہیں ہوئی، وہ اس کے بس سے باہر تھے۔ پھر یہ ایک امرِ واقعہ کا سوال ہو گا، اس پر عدالتیں غور کریں گی، گواہیوں اور شواہد کی بنیاد پر معاملات طے کیے جائیں گے۔‘‘(گیارھواں خطبہ:ص۴۰۵،۴۰۶)
سوال یہ ہے کہ جس قوم کا صدر میثاق کر کے مکر جائے اور توجیہ پیش کرے کہ میثاقِ جمہوریت قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ سمجھے بغیر کہ قرآن حدیث میثاق کی پابندی کا حکم دیتے ہیں، اس قوم کے لیے فزیبلٹی رپورٹ کی کیا اہمیت ہو گی؟ ہماری رائے میں قرآنی حکم ’’اوفوا بالعقود‘‘ اور حدیثِ مبارکہ ’’المسلمون عند شروطھم‘‘ کا فہم مالکیوں کے استدلال کو تقویت بخشتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی کو ہی دین سمجھنے والے انگشت بدنداں رہ جائیں کہ غیر احناف کا استدلال قابلِ قبول’’کیسے ‘‘ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ممدوحؒ کی خو، بات بڑھانے والی ہے، اس لیے بہت صاف صاف کہتے ہیں:
’’ بعض علما کا کہنا ہے کہ خرید وفروخت اور عقود کے معاملات میں امام احمد بن حنبل ؒ کا نقطہ نظر بہت آسان اور وسیع ہوتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبلؒ کے اجتہادات سے اگر خاص طور پر استفادہ کیا جائے تو بیع کے احکام کو زیادہ آسانی کے ساتھ مرتب کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ بیوع کے بارے میں امام مالکؒ کے وضع کردہ اجتہادی قواعد بہت پختہ اور بہتر ہیں۔ ......اس لیے دنیائے اسلام میں آج کا رجحان یہی ہے اور یہ بہت مفید اور مثبت رجحان ہے کہ فقہ اسلامی کے پورے ذخیرے کو سامنے رکھ کر اجتہادی معاملات میں یہ دیکھا جائے کہ ائمہ فقہ کا کون سا اجتہاد ہے جو آج کل کے تقاضوں کے زیادہ مطابق ہے اور آج کل کے مسائل کو زیادہ آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے۔‘‘ (آٹھواں خطبہ: ص ۳۲۱، ۳۲۳)
ڈاکٹر صاحب جس اعلیٰ ظرفی کی سو فی صد توقع کر رہے ہیں ، کم از کم پاکستان کے علما کے لیے تو اس کا پچاس فی صد اظہار بھی سو فی صد ناممکن ہے۔ اگر بات شعوری اور متصلب حنفیوں تک محدود ہوتی تو شاید کسی طور کھینچ تان کر انہیں اجتماعی ملی دھارے میں لایا جا سکتا تھا، لیکن خیر سے یہاں ایسے متعصب، ضدی، تنگ نظر اور فرقہ پرست مینڈکوں کی بہتات ہے جن کے لیے کنواں ہی سمندر ہے۔ بہرحال! ڈاکٹر غازی مرحوم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اسلامی بینکاری کی کامیابی لوگوں کی ’’واقعی ضروریات‘‘ کی تکمیل سے وابستہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ:
’’اگرچہ آج پاکستان میں ایسے جائز ذرائع الحمدللہ موجود ہیں جہاں اس طرح کی رقم لگائی جا سکتی ہے اور جائز طریقے سے گھر بیٹھے آمدنی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بددیانتی اور دھوکہ دہی کا دور دورہ ہے، اس لیے بہت سے لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بینکوں کا نظام چونکہ شروع سے چلا آ رہا ہے، دو سو ڈیڑھ سو سال سے ایک خاص نہج پر قائم ہے، وہاں دھوکہ کے امکانات نسبتاًکم ہوتے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کی واقعی ضرورت ہے کہ ان کے لیے ایسانظام وضع کیا جائے جن کو گھر بیٹھے ماہانہ رقم مل سکے۔ اب چونکہ پاکستان میں بہت سے بینکوں نے اسلامی شعبے بھی قائم کر دیے ہیں، اسلامی برانچیں بھی بنائی ہیں، اس لیے اب یہ نسبتاًآسان ہو گیا ہے اور اسلامی بینکوں کو یا روایتی بینکوں کے جو اسلامی شعبے ہیں یا اسلامی شاخیں ہیں، ان کو یہ کام کرنا چاہیے اور بیوہ خواتین، بوڑھے پنشنرز، بے گھر لوگ، یتیم بچے اور بے سہارا، ایسے حضرات کے لیے شریعت کے مطابق کوئی ایسی اسکیمیں بنانی چاہیےیں جہاں وہ پیسہ لگا سکیں اور ان کو گھر بیٹھے آمدنی ہو سکے۔‘‘(نواں خطبہ: ص ۳۵۰، ۳۵۱)
ربا کی بحث میں ظلم و استحصال کے حوالے سے ناقدین کی تاویلات کو ڈاکٹر غازی مرحوم نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، کہتے ہیں کہ:
’’ ظلم اور استحصال کا بعض حضرات بہت کثرت سے حوالہ دیتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ ظلم اور استحصال کے بار بار حوالے کے باوجود ربا کی بعض قسموں کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں۔ بنک انٹرسٹ کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس میں اس مفہوم میں ظلم اور استحصال نہ پایا جاتا ہو جس مفہوم میں قرآن مجید نے ظلم اور استحصال کو ناجائز قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی رو سے ظلم یہ ہے کہ اصل سرمایے سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے اور یہ بھی ظلم ہے کہ اصل سرمایے سے کم واپس کیا جائے۔‘‘(نواں خطبہ:ص۳۵۷،۳۵۸)
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لاکھ رروپے قرض لیتا ہے اور سال بعد ایک لاکھ واپس کرتا ہے تو کیا وہ اصل سرمایہ واپس کرتا ہے؟ ہماری نظر میں وہ اصل سرمایے سے کم رقم واپس کرتا ہے کیونکہ افراطِ زر کے باعث روپے کی قیمت کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اندریں صورت قرض دینے والا جس رقم سے خود نفع حاصل کر سکتا تھا، اس رقم کو قرض دے کر نہ صرف ایسے نفع سے محروم رہتا ہے بلکہ الٹا اسے اصل رقم کے بجائے(ویلیو کے اعتبار سے) کم رقم ملتی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ بھی’’ منفی ربا‘‘سے ملتی جلتی صورت نہیں ہے؟ کیا یہ بھی عجیب بات نہیں ہے؟ ڈاکٹر محمود مرحوم غالباًقرض کے معاملے میں افراطِ زر جیسے مسئلے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، البتہ افراطِ زر اور اس کی قباحتوں سے وہ بخوبی واقف ہیں:
’’ اقتصادِ کلی کے دوسرے اہداف میں قیمتوں میں استحکام کا معاملہ بھی شامل ہے۔ قیمتوں میں استحکام ریاست کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر قیمتوں میں استحکام نہ ہو تو نہ درآمد درست ہو سکتی ہے نہ برآمد درست ہو سکتی ہے۔ قیمتوں میں استحکام نہ ہو تو تنخواہ دار طبقہ اور محدود آمدنی رکھنے والے لوگ اپنی زندگی کے معاملات کو درست نہیں کر سکتے۔ قیمتوں میں استحکام اس لیے بھی ضروری ہے کہ افراطِ زر جو آج کل زر اعتباری کا ایک لازمی نتیجہ ہو گیا ہے، اسے کم سے کم رکھا جائے۔ جب تک زر اعتباری کا نظام دنیا میں موجود ہے اس وقت تک مکمل طور پر افراطِ زر کو ختم کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ البتہ مناسب اقدامات اور تدبیروں سے اسے کم سے کم رکھا جاسکتا ہے۔ اتنا کم سے کم جو عامۃ الناس کی سکت سے باہر نہ ہو۔ اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ایک متوازن مالیاتی اور زری پالیسی وضع کی جائے جس پر ریاست کے تمام ادارے کام کریں۔ مالیاتی اور زری پالیسی وضع کرنا ریاست کا ہی کام ہے اور یہ ریاست کے اقتصادی اہداف میں سے ایک ہے۔‘‘ (چوتھاخطبہ:ص۱۶۸)
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا یہ کہنا ’’جب تک زر اعتباری کا نظام دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک مکمل طور پر افراطِ زر کو ختم کرنا شاید ممکن نہیں ہے‘‘ اشارہ دے رہا ہے کہ ان کے ذہن میں زرِ اعتباری کا کوئی متبادل نظام موجود ہے، لیکن نجانے انہوں نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ بہرحال! ڈاکٹر غازی ؒ اسلامی بینکاری میں سود کے شائبے تک سے بچنے کی خاطر، جہاں قرض کے معاملے میں افراطِ زر سے چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہاں اتنی نرمی ضرور دکھاتے ہیں کہ:
’’بنکوں کے واقعی اخراجات کو پوراکرنے کے لیے سروس چارج لگایا جا سکتا ہے۔ سروس چارج کے جائز ہونے پر عام طور پر اس دور کے علما کرام کا اتفاق ہے۔ سروس چارج کے قواعد و ضوابط بہت سے علمائے کرام نے مرتب فرمائے ہیں۔‘‘ (دسواں خطبہ: ص ۳۷۲)
سود سے پاک اسلامی بینکاری عملی طور پر کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اصولی طور پر کس قسم کا معاشی ڈھانچہ تشکیل پانا چاہیے جو اپنے ثمرات سے عامۃالناس کو نواز سکے؟ اس پر بھی ڈاکٹر محمو احمد مرحوم نے خوب اظہارِ خیال کیا ہے:
’’اسلامی بینکاری کو چاہیے کہ وہ مائیکرو فائنانسنگ پر خاص توجہ دے۔ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینا ملکی معیشت کا تقاضا بھی ہے، عامۃ الناس کی ضرورت بھی ہے اور اسلامی بینکاری جتنی تیزی سے اور جتنے موثر انداز میں چھوٹی معیشت میں کامیاب ہو سکتی ہے، اتنی تیز رفتار کامیابی بڑی معیشت میں مشکل ہے۔ بڑی معیشت میں اسلامی اصلاحات کے کامیاب ہونے میں خاصا وقت لگے گا۔ مبنی بر شراکت تمویل کو یعنی participatory financing کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ یہ اسلامی بینکاری کا وہ کام ہے جو اسلامی بینکار کو کرنا چاہیے۔ ......اسلامی بینکاری میں نفع اگر آئے تو وہ دو طریقے سے آنا چاہیے۔ یا تو وہ نفع اس چیز کا نفع ہو جس کے نتیجے میں کوئی جائیداد یا اثاثہ جات assets وجود میں آئے ہیں یا کوئی ویلیو value وجود میں آئی ہے، یعنی value creation ہوئی ہے یا asset creation ہوئی ہے۔ محض opportunity cost یا وقت کی قیمت کی بنیاد پر آمدنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آمدنی محض وقت کی قیمت کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو چاہے اس کا جو بھی نام رکھا جاے اور کسی بھی تاویل سے کھینچ تان کر اس کا جواز دریافت کر لیا جائے، وہ اسلام کی روح اور مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسلام کی روح اور تقاضوں سے ہم آہنگ وہی تمویل اور سرمایہ کاری ہے جس کے نتیجے میں عملاًکوئی تجارت پیدا ہو، کوئی صنعت وجود میں آئے، کوئی خدمت وجود میں آئے، کوئی جائیداد وجود میں آئے۔ لہٰذا جتنی وسعت زر میں ہو، اتنی ہی وسعت اثاثہ جات یا صنعتوں یا تجارت میں ہونی چاہیے۔ توسیع زر اور توسیع اثاثہ جات یہ دونوں ایک ساتھ اور متناسب انداز میں ہونے چاہییں۔‘‘ (دسواں خطبہ:ص۳۸۵،۳۸۶)
اپنے لوگوں کی نالائقی اور مغربیوں کی فنی پختگی سے ڈاکٹر صاحب خوب آگاہ ہیں اور آج کی عالم گیر فضا کے تقاضوں پر بھی ان کی نظر ہے، اس لیے ایک حسرتِ تعمیر ہے جو درویش صفت ڈاکٹر غازیؒ کے اندر ہی اندر غالبؔ کے اس کہے کے مطابق مچل رہی ہے :
گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا
وہ جو رکھتے تھے ہم اِک حسرتِ تعمیر، سو ہے
لیجیے! ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کی حسرتِ تعمیر ملاحظہ کیجیے:
’’ کسی تجربے کی فنی خرابی کا ذمہ دار اسلامی بینکاری کو یا اسلامی شریعت کے احکام کو نہ ٹھہرایا جائے۔ اسلامی قوانین کے نفاذ اور اسلامی اصلاحات کی کامیابی کے لیے محض دینی جذبہ کافی نہیں ہے۔ اس کام کے لیے دنیا میں رائج الوقت تجربات سے واقفیت بھی ازحد ضروری ہے۔ جرمنی میں مرچنٹ بینکنگ کا تجربہ بہت کامیاب بتایا جاتا ہے۔ مرچنٹ بینکنگ کا تصور اسلامی بینکاری کے احکام سے خاصا قریب ہے۔ لہٰذا اگر جرمنی میں مرچنٹ بینکنگ کامیاب ہے تو اس سے استفادہ کر کے اس کو اسلامی بینکاری کے تقاضوں کے مطابق ڈھالاجا سکتا ہے۔ .......مغربی بینکاری اور اسلامی بینکاری کے درمیان ربط اور تعلق کی ممکنہ نوعیت کیا ہے؟ اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ ایک ممکنہ تعلق تو دشمنی اور دعوتِ مبارزت کا ہو سکتا ہے۔ ایک اور نوعیت مقابلہ اور منافرت کی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں جو تعلق مناسب تر اور بہتر معلوم ہوتا ہے، وہ تعاون اور تکامل کا ہے۔ اگر اسلامی بینکاری کے ادارے مغربی بینکاری کے اداروں سے شریعت کے احکام اور اخلاقی ضوابط کی مکمل پابندی کے ساتھ انسانی مقاصد میں تعاون کریں، عامۃ الناس کی بہبود اولین ترجیح ہو اور ان میدانوں پر توجہ دی جائے جو ابھی خالی ہیں، جن میں کام نہیں ہوا تو اسلامی بینکاری کے لیے مغربی دنیا میں پنپنا نسبتاًآسان ہو سکتا ہے۔ دشمنی اور دعوتِ مبارزت کا نتیجہ سوائے تباہی اور مشکلات کے اور کچھ نہیں ہو گا۔ ‘‘(دسواں خطبہ:ص۳۸۶،۳۸۷،۳۸۸)
ڈاکٹر غازیؒ نے خوب فرمایا کہ محض دینی جذبہ کافی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دینی جذبہ بھی کفایت کر جاتا ہے بشرطیکہ وہ واقعی دینی جذبہ ہو۔ ہمارے ہاں جس قسم کے مباحث دینی جذبے کی نشو و نما کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے مولانا رومیؒ کی ایک حکایت یاد آ جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ’’ایک شخص نے دوسرے کو تھپڑ رسید کیا، جواب میں دوسرے نے بھی چپت رسید کر دی۔ تھپڑ مارنے والے نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو اور مجھے مارنے کی حسرت پوری کر لو۔ میں نے تجھے تھپڑ مارا تو تڑاخ کی آواز آئی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ آواز میرے ہاتھ سے پیدا ہوئی ہے یا تیری گدی سے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے تھپڑ کی تکلیف اور درد سے مجھ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ آواز پر کان دھروں۔ تجھ کو چونکہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے اس نکتے پر تو غور کرتا رہ۔ جو درد میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو ایسی باریکیاں اور نکتے نہیں سوجھتے۔‘‘ اب ذرا اپنے سماج میں برپا شور و غوغا پر توجہ فرمائیے کہ مسلمانوں کی دینی غیرت بیدار کرنے کی غرض سے کیسے کیسے نکات اٹھائے جاتے ہیں اور دماغ سوزی کے کیسے کیسے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس وقت بے چارہ تھپڑ رسیدہ سماج، رخسار سہلا رہا ہے اور علمائے دین کو مسلکی اٹھکیلیاں سوجھی جا رہی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی جذبے کے عناصر ترکیبی اگر اخلاص، احسان، ایثار، اخوت اور باہمی حسن سلوک سے عبارت ہوں تو کم از کم ایک راستہ ضرور دکھائی دینے لگتا ہے، پھر مسافت چاہے طویل ہی ہو، گراں نہیں گزرتی۔
جہاں تک بینکاری کے شعبے میں مغرب سے تعاون کا تعلق ہے، تو فکر ولی اللٰہی ایسے تعاون کو منزل آشنا تسلیم نہیں کرتی۔ حالیہ دور میں معیشت کی اہمیت اور اس میں بینکاری کے کلیدی کردار کو دیکھتے ہوئے یہ اخذ کرنا چنداں مشکل نہیں کہ کلی نظام کو بدلنے کے لیے معاشی و بینکاری نظام میں مطلوبہ تبدیلی انتہائی ناگزیر ہے۔ شاہ ولی اللہؒ مطلوبہ تبدیلی کے بجائے نظام کا مکمل خاتمہ (فک کل نظام) چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی نظام میں کی گئیں جزوی تبدیلیاں مطلوبہ مقاصد نہیں دے سکتیں، اس لیے وہ موجود نظام کی بساط مکمل طور پر سمیٹ دینے کے حامی اور داعی ہیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹر غازیؒ جزوی تبدیلیوں کے ذریعے سے، موجود معاشی نظام کی بنیادی ساخت کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک قدم مزید بڑھتے ہوئے تبدیلی کے اس ارتقائی عمل میں تعاونی انداز و اطوار اپنانے پر زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم گزارش کریں گے کہ مغربی اور اسلامی بینکاری کے درمیان تعاون پر مبنی تعلق کیا شریعت کے اصولِ تدریج کے بغیر ممکن ہے؟ ڈاکٹر محمود مرحوم تو صرف اور صرف ناسخ احکام کے قائل معلوم ہوتے ہیں، پھر کس اصول کے تحت اور کس جواز کی بنا پر تعاونی تعلق قائم کیا جائے گا؟ کیا ناسخ احکامات میں اس قدر لچک موجود ہے کہ وہ تعاونی تعلق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں؟ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اصولِ تدریج کو صدرِ اسلام کے زمانے سے مخصوص قرار دے، ناسخ و منسوخ کے تحت احکامِ شرعیہ کو انتہائی ٹھوس اور استوار سمجھے اور پھر ناسخ احکامات کی تنفیذمیں عملی مسائل بھانپ کر خود ساختہ تدریج قائم کرنے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس خود ساختہ تدریج میں ’’منسوخ‘‘ احکامات کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہ ہو، بلکہ اپنی ذہنی اختراع کے مطابق اصلاحِ احوال کے لیے کوشاں ہو۔ اس سارے عمل کو، اگر نرم زبان استعمال کی جائے، داخلی تضاد کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم پر اس تنقید کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم شاہ ولی اللہؒ سے اتفاق کرتے ہوئے نظام کے مکمل خاتمے (فک کل نظام) کے حامی ہیں اور مغربی نظامِ معیشت و بینکاری کے ساتھ مخاصمانہ رویہ اپنانا چاہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نظام کا مکمل خاتمہ کسی ’’طوفانِ نوح‘‘ کا تقاضا کرتاہے اور مشیت الٰہی اس تقاضے کے ساتھ معلوم نہیں ہوتی۔ ہمیں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے جس میں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہود و منافقین کے مقابل، بتدریج تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تدریجی تبدیلی میں مبارزت اور تعاون ساتھ ساتھ شریک رہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ آج مغربی بینکاری کے ساتھ تعاونی تعلق ’ ہی‘ بہتر رہے گا، یک رخی پالیسی اپنانے کے مترادف ہوگاجس کا منطقی نتیجہ پسپائی و ہزیمت کی صورت میں برآمد ہو گا۔ اس لیے ڈاکٹر غازیؒ کی یہ حد بندی بہت قابلِ غور ہے کہ ’’ اگر اسلامی بینکاری کے ادارے مغربی بینکاری کے اداروں سے شریعت کے احکام اور اخلاقی ضوابط کی مکمل پابندی کے ساتھ انسانی مقاصد میں تعاون کریں‘‘۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخاصمت و مبارزت کے لمحات بھی آتے جاتے رہیں گے۔ شاہ ولی اللہؒ غالباًتدریجی تبدیلی کے آخری مرحلے یعنی خطبہ حجۃالوداع سے استدلال کرتے ہوئے نظام کے مکمل خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ یہ نہ صرف شریعت کامقصد ہے بلکہ عالمی سطح پر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی ایک سبیل بھی ہے، لیکنحجۃ الوداع سے پہلے کیے گئے اقدامات کے مراحل سے گزرے بغیر ایسا کرنا بلکہ ایسا سوچنا بھی محال اور نا ممکنات میں شمار ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرسودہ نظام کا مکمل خاتمہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا:
’’آج سے ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ تم صرف اصل رقم کے حق دار ہو۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود کو ختم کر دیا جائے۔ عباس بن عبدالمطلب کا جو سود دوسروں کے ذمہ واجب ہے، وہ ختم کیا جاتا ہے۔‘‘
تو اس سے پہلے اس سادہ زرعی دور کے تقاضے ملحوظ رکھے اور مقصد (رباکے خاتمے)کے واضح تعین کے باوجود احکامِ ربا کی نزولی ترتیب کے تتبع میں بتدریج عملی اقدامات اٹھائے۔واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہؒ کے نام لیواؤں نے (فک کل نظام) کی غلط تعبیر ان کے سر منڈھ دی ہے حالانکہ شاہ صاحب کا اصولی موقف بھی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں ہے۔ فرماتے ہیں :
’’واضح ہو کہ امت کی درستی اور سیاست کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی طاعت کی دو حدیں قرار دی جائیں، ایک اعلیٰ اور دوسری ادنیٰ۔ پس اعلیٰ وہ ہے جس سے پوری طرح پر مقصود حاصل ہو جائے اور ادنیٰ کے معنی یہ ہیں کہ اس سے اس قدر مقصود حاصل ہو کہ اس کے بعد کا درجہ لحاظ کے قابل بھی نہ ہو۔ ......اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حالت کو چھوڑ کر ادنیٰ حالت پر ہی اکتفا کر لیا جائے کیونکہ یہ اعلیٰ حالت سابقین امت کا مشرب اور مخلصین کا حصہ ہے۔ ایسے درجے کو بالکل ترک کرنا لطفِ الٰہی کے منافی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ادنیٰ حالت کی بخوبی توضیح کر کے اس کے ساتھ لوگ مکلف قرار دیے جائیں اور اس سے زائد اور اعلیٰ امور کی طرف بھی مائل کیے جائیں۔‘‘ (حجۃ اللہ البالغۃ: باب المصالح المقتضےۃ لتعیین الفرائض و الارکان والاٰ داب و نحوذٰلک)
بہرحال، خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کا ذکر ہمارے لیے اس بات کی علامت ہے کہ آج کی عالم گیریت کی فضا میں جب ہم نظام کے مکمل خاتمے کے درپے ہوں یعنی سابقین امت اور مخلصین کے درجے میں آنا چاہیں تو ہمیں اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ دوسروں کے ذمہ واجب اپنا سود ختم کر سکیں۔ معاف کیجیے گا، اس وقت تومعاملہ کافی دگرگوں ہے کہ دوسروں کا سود ہمارے ذمے واجب الادا ہے۔ تو کیا پھر صورتِ حال میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ ہاں! کیوں نہیں، کہ اقبال ؔ نے کہا تھا:
وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے
جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا
اسلامی بینکاری کے ضمن میں بیع مرابحہ پر اشکالات وارد ہوتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد مرحوم نے اس پر بھی گفتگو کی ہے:
’’ بیع مرابحہ کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری کا کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو تجارت کی ایک شکل ہے جس سے جزوی طور پر سرمایہ کاری کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ بیع مرابحہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو اپنا کوئی سودا فروخت کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اس کو کسی سودے کے حصول میں جو قیمت یا لاگت پڑے گی، اس پر وہ اتنے فی صد کے حساب سے نفع لے گا۔ .......بیع مرابحہ کو امپورٹ ایکسپورٹ میں خاص طور پر اور انڈسٹری کے دوسرے معاملات میں عام طور پر آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاًایک شخص کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ایک کروڑ روپے کی مشینری اس کو جرمنی سے درکار ہے۔ اس کے پاس ایک کروڑ روپے نہیں ہیں۔ اب روایتی بینکاری کے طریقِ کار میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بنک کے پاس جائے اور ایک کروڑ روپے قرض لے اور اس پر دس فی صد سود دینے کا وعدہ کرے اور وقت آنے پر ایک کروڑ کے بجائے ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی رقم ادا کرے اور قرض کی یہ رقم لے کر اپنی مشینری منگوا لے۔ یہ تو یقیناًسود ہے۔ اس کے مقابلہ میں بیع مرابحہ کا طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ بنک ایک کروڑ روپے سودی قرض دینے کے بجائے از خود وہ مشینری درآمد کرے۔ اس کے بعد خریدار کو بتائے کہ یہ مشینری بنک کو ایک کروڑ روپے میں پڑی ہے۔ اس پر دس فی صد بنک کا نفع ہو گا۔ یوں وہ خریدار ایک کروڑ دس لاکھ روپے ادا کر کے مشینری بنک سے خرید لے۔ یہاں قرضوں کا لین دین نہیں ہے۔ یہاں حقیقی اصول کا یعنی اثاثہ جات کا اور tangible assets کا کاروبار ہے اور شریعت کے احکام کے مطابق بیع کی ایک شکل ہے۔ اس لیے یہ جائز ہے۔‘‘(آٹھواں خطبہ:ص۳۲۳،۳۲۴)
اگرچہ ایسی بیع مرابحہ کے حق میں حیلے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عنوان اور مندرجات کی بحث (العبرۃ بالمضمون والجوہر و لیس بالصورۃ والمظھر) یہاں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ خود ڈاکٹر صاحب نے نویں خطبے میں علامہ ابنِ قیم ؒ کے حوالے سے تقریباًیہی نکتہ اٹھایا ہے:
’’علامہ ابنِ قیم ؒ نے ایک جگہ حیلے سے بحث کی ہے اور خاص طور پر سودی حیلہ کاری کا ذکر کیا ہے۔ اس سیاق و سباق میں انہوں نے لکھا ہے کہ ربا کی حرمت کو کسی متعین صورت یا متعین الفاظ تک محدود کرنا درست نہیں ہے بلکہ ربا کی حرمت کا تعلق اس حقیقت کی وجہ سے ہے جس سے وہ تجارت اور خرید و فروخت سے ممیز ہوتا ہے۔ یہ حقیقتِ ربا جہاں بھی پائی جائے گی، وہاں حرمت کا حکم بھی منطبق ہو گا، چاہے اس میں الفاظ کوئی بھی اختیار کیے جائیں۔ شریعت کے احکام کا دارو مدار حقائق پر ہوتا ہے، الفاظ اور عنوانات پر نہیں ہوتا۔‘‘(نواں خطبہ:ص۳۵۴)
لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر غازیؒ کا رجحانِ طبع ، بیع مرابحہ جیسے عنوانات و مندرجات کی موافقت میں ہے، تبھی تو انہوں نے گیارھویں خطبے(ص۴۰۲،۴۰۳) میں اس کی وکالت کی ہے۔ شاید اسی لیے بینکاری کے بعض معاملات میں وہ حیلے کو اہمیت دیتے ہیں:
’’بظاہر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ روایتی اور اسلامی بینکاری کے معاملات میں فرق زیادہ نمایاں طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن شریعت کے بہت سے احکام میں ایسا ہے کہ جائز اور ناجائز میں جو فرق ہے، وہ طریقِ کار کا فرق ہوتا ہے۔ بہت سے معاملات شریعت میں جائز ہیں، بہت سے ناجائز ہیں۔ ایک ہی کام کو ایک طریقے سے کیا جائے گا تو جائز ہوگا دوسرے سے کیا جائے گا تو ناجائز ہو گا۔‘‘(دسواں خطبہ:ص۳۸۱)
لیکن امام شاطبی ؒ کے حوالے سے ہمارے ممدوحؒ ہمیں اس نکتے سے آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں:
’’النظر فی مآلات الافعال معتبر شرعا، کہ کسی بھی معاملے کے انجام کی بنیاد پر اس معاملے کا فیصلہ کرنا شریعت کا ایک طے شدہ اصول ہے۔ لہٰذا اسلامی بینکاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے معاملات جہاں فنی اعتبار سے سو فی صد درست ہوں، وہاں اسلامی اعتبار سے بھی مکمل طور پر شریعت کے احکام کے پابند ہوں۔‘‘(دسواں خطبہ:ص۳۸۵)
فیصلہ کرنا کافی مشکل ہے کہ بیع مرابحہ کوآخر کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ اگر صرف اور صرف ’’ انجام‘‘ دیکھا جائے تو قرض لینے والے کو ایک کروڑ قرض پر، دونوں صورتوں میں ایک کروڑ دس لاکھ ادا کرنے پڑتے ہیں اور اگر ’’طریق کار‘‘ دیکھا جائے تو جواز بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسلامی بینکاری میں بیع مرابحہ جیسے طریق ہائے کار کی اجازت عبوری دور کے لیے ہونی چاہیے، یعنی انہیں’’ اصولاً‘‘ تسلیم کرنے کے باوجود ’’مقصود‘‘ کے درجے میں ہرگز نہ رکھا جائے۔ اسلاف کا طرزِ عمل ایسے معاملات میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہی دیکھ لیجیے:
’’ ایک شخص نے امام( ابوحنیفہ ؒ )سے قرض لیا ہوا تھا۔ امام صاحب کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کسی (دوسرے)شخص نے روک کر مسئلہ پوچھنا چاہا۔ امام صاحب رک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ صاحب جو مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، وہ سورج کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے ایک دیوار کے سایے میں کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب کو بھی دعوت دی کہ دیوار کے سایے میں آ جائیں۔ امام صاحب دیوار کے سایے میں تشریف نہیں لائے، دھوپ میں کھڑے کھڑے جواب دیتے رہے۔ جب خاصی دیر ہوئی تو ان صاحب نے پھر اصرار کیا کہ دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے دیوار کے سایے میں آ جائیں۔ امام صاحب پھر بھی سایے میں تشریف نہ لائے اور اسی طرح جواب دے کر تشریف لے گئے۔ کوئی شاگرد یا نیاز مند جو ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ ان صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود دیوار کے سایے میں کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ وہ مکان جس کی دیوار کا سایہ تھا، وہ میرے فلاں مقروض کا مکان تھا۔ میں اس کی دیوار کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ میرے مقروض ہیں۔ مقروض کی دیوار سے اتنا سا فائدہ اٹھانابھی کہ اس کے سایے میں کھڑے ہو جائیں، امام صاحب نے اس حدیث (کل قرض جر نفعاًفھو ربا) کے خلاف سمجھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ’’کل قرض جر نفعاًفھو ربا‘‘ کے حکم پر عمل درآمد کے بارے میں ائمہ کرام کا طرزِ عمل کیا تھا۔ وہ کتنے محتاط تھے اور کتنی جز رسی اور باریک بینی کے ساتھ وہ ان معاملات پر نظر رکھتے تھے۔‘‘ (ساتواں خطبہ: ص ۲۸۲، ۲۸۳)
ہماری روایتی علمی تاریخ میں، ربا کے باب میں ایک اختلافی واقعہ موجود رہا ہے۔ اس واقعے کی بابت خود کو مسلم علمی روایت کا پابند بناتے ہوئے ڈاکٹر غازی مرحوم فرماتے ہیں کہ:
’’ یہ معاملہ حدیث اور فقہ کے ادب میں ’’ضع وتعجل‘‘ یا ’’ضعوا وتعجلوا ‘‘کے عنوان سے مشہور ہے۔ ضعوا وتعجلوا صیغہ جمع میں ہے اور ضع وتعجل صیغہ مفرد میں ہے۔ ضع وتعجل کے لفظی معنی یہ ہیں کہ اصل مطالبے میں سے کمی کر دو اور بقیہ رقم پیشگی وصول کر لو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو النضیرکے موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ اس موقع پر یہ طے ہوا تھا کہ بنوا لنضیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیا جائے۔ جب وہ جلا وطن ہونے لگے اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں کی رقمیں بنو نضیر کے ذمے واجب الادا ہیں۔ اس طرح کے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا: ’’ضعوا وتعجلوا‘‘۔ یعنی جو رقم ایک مدت کے بعد واجب الادا ہو گی، وہ ابھی وصول کر لو اور اصل مطلوبہ رقم میں سے کچھ حصہ کم کر دو۔ یہ مسئلہ غزوہ بنی النضیر کے دوران پیش آیا جو مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک ربا کی متعدد آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اس لیے ائمہ اربعہ کا خیال ہے کہ ربا کی آیات کے نازل ہونے کے بعد اس طرح کی اجازت اگر شریعت میں تھی تو وہ منسوخ ہو چکی ہے اور اب ’’ضع وتعجل‘‘ کے اصول پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ کچھ دوسرے حضرات کا شروع سے یہ خیال رہا ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ تابعین میں حضرت امام نخعیؒ اور بعد کے فقہا میں شیخ الاسلام علامہ ابنِ تیمیہؒ اور علامہ ابنِ قیمؒ کی یہی رائے ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ضع وتعجل کااصول باقی ہے اور اس پر بعد میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ دو اصول پیشِ نظر رکھے جائیں۔‘‘(نواں خطبہ:ص۳۵۵)
بڑی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر غازی مرحوم اپنے محاضرات میں کہیں تو مستنبط اصولوں کو نصوص کے دائرے میں لے آئے ہیں اور کہیں منصوص احکام کو منسوخ قرار دے کر مستنبط اصولوں سے بھی بہت پیچھے لے گئے ہیں۔ درج بالا اقتباس ہی دیکھ لیجیے۔ کیا اس میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کوتقریباًنظر انداز کیے جانے کا تاثر نہیں ملتا؟اور کیا یہ منسوخ کے نام پر نہیں ہو رہا؟ کیا اس طرزِ عمل سے قرآن و سنت پر فقہا کی عملی فوقیت قائم نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسا طرزِ عمل ہے؟حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم اصولِ تدریج کی واقعیت اور حکمت سے خوب واقف ہیں، اسی لیے ساتویں خطبے میں (ص۲۷۵پر) فرماتے ہیں کہ ’’ربا کی حرمت شریعت کے بہت سے احکام کی طرح بالتدریج نازل ہوئی ہے۔ شریعت کا یہ مزاج رہا ہے کہ بہت سی اصلاحات میں بہت سے اہم معاملات میں احکام کے نزول میں تدریج سے کام لیا گیا ہے۔ اگر کوئی عادت خاص طور پر عادتِ قبیحہ لوگوں میں بہت جاگزین تھی تو اس کو بیک وقت ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس تدریج کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کوئی غیر عملی نظام نہیں ہے۔‘‘ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت کے اصولِ تدریج کو ناسخ و منسوخ کے نام پرصدرِ اسلام کے لیے مخصوص کر دینے کے رویے نے ہی اب شریعت کو غیر عملی نظام بنا دیاہے۔ اس موضوع پر قدرے تفصیلی و اصولی بحث کے لیے ماہنامہ الشریعہ اگست ۲۰۰۶ء میں ہمارا مضمون ’’معاصر تہذیبی تناظر میں مسلم علمی روایت کی تجدید‘‘ دیکھ لیجیے۔ بہرحال! زیر نظر محاضرات میں بعض ایسے نظری اور اصولی نکات شامل ہیں جن کی تنقیح ضروری ہے۔ خاص طور پر موجودہ ماحول میں جبکہ تکنیکی ترقی نے انسانی زندگی کے مادی و غیر مادی پہلوؤں کو خاصا متاثر کیا ہے، ایسے مباحث کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر غازی مرحوم کہتے ہیں کہ:
’’جہاں تک قرآن کریم اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تعلق ہے تو وہ ایک دائمی اساس ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمیشہ عمارت کی تعمیر ہوتی رہے گی۔ ان دو بنیادوں کے ساتھ ساتھ ائمہ اسلام کے وہ اجتہادات بھی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں جن پر اتفاقِ رائے رہا ہے، جن پر اسلامی تاریخ میں تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ ان کی حیثیت بھی اسی طرح دائمی ہے جس طرح قرآن کریم اور سنتِ ثابتہ کی حیثیت دائمی ہے۔ ......جس تعلیم کو بقا ہے، جس حکم کو دوام ہے، وہ قرآن مجید کے احکام ہیں، وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں اور ائمہ اسلام کے متفقہ اجتہادات ہیں۔‘‘(پہلا خطبہ:ص۱۹)
ڈاکٹر صاحب اسی نکتے کا اعادہ فرماتے ہیں :
’’الاصل فی المعاملات الا باحۃ، اس کے معنی یہ ہیں کہ کاروبار کی ہر قسم لین دین کی ہر قسم جائز ہے، بشرطیکہ وہ ان حرام عناصر سے پاک ہو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جدید نوعیت کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ کسی روایتی عربی اسلامی اصطلاح کے تحت آ سکتے ہوں یا نہ آ سکتے ہوں، وہ سب جائز ہیں بشرطیکہ وہ قرآن کریم اور احادیث کی نصوص سے متعارض نہ ہوں اور ان متفق علیہ قواعد سے متعارض نہ ہوں جو فقہائے اسلام نے قرآن کریم اور سنت سے اخذ کیے ہیں۔‘‘(آٹھواں خطبہ:ص۳۰۱)
ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ معاملات میں اصل اباحت ہے اور اس بنیاد پر تجارت و کاروبار کی کوئی بھی صورت قابلِ قبول ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ قرآن و احادیث کی نصوص سے متعارض نہ ہو اور اسی سانس میں معاصر ین کو پابند کرنے کی خاطر یہ حکم لگا رہے ہیں کہ تجارت و کاروبار کی کوئی ممکنہ صورت ان متفق علیہ قواعدسے بھی متعارض نہیں ہونی چاہیے جو فقہائے اسلام نے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ متفق علیہ قواعد اتنی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں کہ انہیں بھی قرآن و سنت کی نصوص کے متوازی حیثیت دے کر ہر زمانے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے لازمی قرار دیا جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ان قواعد کو بطور قواعد، اصولاًقرآن و سنت میں ہی کہیں مذکور ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سے نتائج کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ فرق مرتب نہ ہو، یعنی معاصرین بھی قرآن و سنت سے اخذ کر کے ویسے ہی قواعد لے آئیں، لیکن اس کے باوجود اس عمل کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح حقیقت میں ہر دن نیا دن ہوتا ہے (کل یوم ھوفی شان) اگرچہ بعضوں کے نزدیک ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ نتائج کی خارجی یکسانیت کے باوجود مذکورہ عمل سے حقیقی فرق ظہور پذیر ضرور ہوتا ہے اگرچہ یہ فرق ظاہر بینوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ بقول اقبالؔ :
اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن!
جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے، وہ نظر کیا!
اس لیے ہمیں کہنے دیجیے کہ جوہری اعتبار سے یہ حقیقی فرق، سماج کے فکری جمود کے لیے ضربِ کلیم ثابت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں تخلیقی سرگرمیوں کا ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایسا ماحول ہی سماج کی واقعی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ غیر جانب داری سے ذرا غور تو کیجیے کہ کل یوم ھوفی شان قرآن مجید کا انتہائی مختصر حصہ ہے۔ اس کی یہ شان ہے کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں تو پھر پورے قرآن مجید کو ائمہ اربعہ یا کبار فقہا کے مستنبط اصولوں میں محصور کر دینے کا عمل اپنے اندر آخر کتنا شرعی جواز رکھتا ہے؟ لہٰذا کل یوم ھوفی شان جیسی قرآنی آیات بہت صراحت سے راہنمائی کرتی ہیں کہ زندگی مسلسل ظہور میں ہے۔ ظہور کا تسلسل، لازمی طور پر انسانوں اور سماج پر اثرانداز ہوتا ہے اور اس اثر پذیری سے سماجی تقاضے بھی یقینی طور پر بدلتے رہتے ہیں۔ بدلے ہوئے تقاضے بدلے ہوئے رویوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو سماج اور جو زمانہ ان مطالبوں کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو موجودہ زمانے میں مسلم سماج کا ہوا ہے۔ شاید شریعت اسلامی کے اسی پہلو کی ترجمانی کرتے ہوئے حکیم الامت علامہ محمد اقبالؒ نے فرمایاتھا:
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
سرِ آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی !
اس لیے کم از کم نظری اعتبار سے ہمیں بہت واضح ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کے متوازی کسی بھی قاعدے کو اس طرح لزوم کے درجے میں اصولاًنہیں لیا جا سکتا جس طرح ڈاکٹر غازی مرحوم فرما رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیان کردہ نظری منہج، صحیح معنوں میں ایسا علمی رویہ تشکیل کرسکتا ہے جو اسلام کو مطلوب ہے اور جو معاصر مسائل کے حل کے لیے اصولیین کی ایک جماعت بھی سامنے لا سکتا ہے۔ لیکن حد تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مقام پر مستنبط اصولوں کو منصوص حیثیت دے دی ہے:
’’کسی معاملے کے ربا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جہاں نصوص کی بنیاد پر کیا جائے گا، قرآن کریم اور احادیث کے واضح احکام کو سامنے رکھ کر کیا جاے گا ، وہاں معاملات کے بارے میں عمومی قواعد کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ معاملات کے بارے میں شریعت کے عمومی قواعد میں کچھ تو وہ ہیں جن کا قرآن کریم اور احادیث میں صراحت کے ساتھ تذکرہ ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ صراحت کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن فقہائے اسلام نے قرآن مجید کی متعدد نصوص اور متعدد احادیث سے ان اصولوں کا استنباط کیا ہے، اس لیے ان کی حیثیت بھی منصوص اصولوں کی ہے۔‘‘ (نواں خطبہ:ص۳۵۶)
گویا ڈاکٹر محمود احمد مرحوم کے نزدیک شریعت دو کے بجائے تین عناصر پر مشتمل ہے۔ وہ بصد اصرار اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہی الفاظ ملاحظہ کر لیجیے:
’’شریعت نے کسی ڈھانچے کو کوئی تقدس عطا نہیں کیا، نہ کسی ڈھانچے کو دوام بخشا۔ دوام صرف اور صرف قرآن مجید کی نصوص، سنت کے احکام اور ان دونوں کی بنیادوں پر مدون کیے جانے والے متفق علیہ احکام کو حاصل ہے۔ ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر یعنی قرآن کریم کی نصوص، سنتِ مبارکہ اور امتِ مسلمہ کے متفق علیہ قواعد و ضوابط کی بنیاد پر مسلمانوں نے وقتاًفوقتاًمختلف انداز کے ڈھانچے اپنائے۔‘‘(گیارھواں خطبہ:ص۴۱۲)
آج ہمارے ممدوحؒ نے شریعت میں قرآن و سنت کے ساتھ متفق علیہ قواعد کو شامل کر لیا ہے، کل کلاں کوئی صاحب کسی اور چیز کو شامل کرلیں گے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر اپنا پنا حسنِ کرشمہ ساز ہو گا اور خرد ، جنوں اور جنوں ، خرد قرار پائے گا۔ یوں اجتہاد سے بچنے کے لیے کیا جانے والا یہ ’’اجتہاد‘‘ دین کو چوں چوں کامربہ بنا دے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر غازیؒ ایک طرف متفق علیہ قواعد کو قرآن و سنت کے متوازی لے رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن کریم کہنے کے بجائے قرآن کریم کی نصوص کہہ کر غالباًقرآن مجید کے ایک خاص حصے کو ہی شریعت کے دایرے میں شامل کر رہے ہیں۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ اس موضوع پر چونکہ ہم اپنی بے لاگ رائے کا اظہار ماہنامہ الشریعہ دسمبر۲۰۰۶ میں بعنوان ’’قدامت پسندوں کا تصورِ اجتہاد‘‘ کر چکے ہیں، اس لیے اسی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔
انسانی زندگی کی بقا کو ملزوم اور ضروریاتِ زندگی میں شامل اشیا پر خواص کا تصرف اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمود احمدغازی مرحوم نے اس موضوع پر یوں لب کشائی کی ہے:
’’ان ممانعتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی ممانعت بھی کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اور عام انسانوں کا ان پر حق یکساں ہے۔ جیسے ایک دریا ہے۔ ..... یہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر جانور کے لیے ہے۔ اب کوئی شخص دریا کے کنارے ہتھیار لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک پیسے نہیں دو گے، پانی نہیں دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو پانی کھلے دریاؤں میں سمندروں میں اور کھلے چشموں میں اور آبشاروں میں آ رہا ہے، وہ تمام لوگوں کی اور اس ملک اور علاقہ کے تمام باشندوں کی ملکیت ہے، اس پر کسی ایک شخص کا قبضہ نہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ اگر کچھ لوگ سفر پر جا رہے ہوں، ایک شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے اور دوسرا محتاج ہے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ جو زائد از ضرورت پانی ہے، یہ دوسرے کو ویسے ہی دے دو، فروخت نہ کرو۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ حرمت قانونی انداز کی ہے ...... بیشتر فقہا کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی نوعیت کی ہدایت ہے۔‘‘ (پہلا خطبہ: ص ۶۲)
ڈاکٹر صاحب نے عام انسانوں کے لیے پیدا کی گئیں چیزوں میں سے ’’دریا‘‘ کی مثال دی ہے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی ’’ذہانت‘‘ ابھی تک کوئی ایسا اصول اختراع نہیں کر سکی جس کی بنیاد پر دریاؤں پر بھی ان کی جارہ داری قائم ہو جائے۔ اس سلسلے میں جب وہ کوئی گل کھلائیں گے تو ’’دریا‘‘ کی مثال بھی عنقا ہو جائے گی اور بات آکسیجن تک آ جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کا ’’یکساں حق‘‘ کیا صرف اور صرف پانی تک محدود ہے؟ کیا انسان صرف اور صرف پانی کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے؟ آج زمین کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں تقریباًاتفاقِ رائے پایا جاتا ہے کہ وہ نجی ملکیت میں نہیں دی جاسکتیں، مثلاًقدرتی گیس، پٹرول، سونا چاندی و دیگر معدنیات وغیرہ تو پھر زمین کے اوپر موجود پیداوار کو نجی تصرف میں کیوں دے دیا گیا ہے؟ وہ زمین جو مدفون خزانے رکھے اور وہ زمین جو پوشیدہ خزانے رکھے، آخر کو زمین ہے، اس میں فرق کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ ذرا غور کیجیے کہ سونے کا بنفسہ، انسان کی بقا سے انسان کی زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کے باوجود آج کے انسان کا اجتماعی ضمیر سونے کی کانوں کو اس لیے نجی ملکیت میں دینے کو تیار نہیں کہ اس سے پورا معاشی نظام تتربتر ہوسکتا ہے جس کے نتیجے میں سماجی نظم برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو پھر ایسی اشیا جو انسانی بقا کے لیے لازم ہیں اورضروریاتِ زندگی میں شمار ہوتی ہیں اور اسی زمین سے پیداوار کی شکل میں حاصل ہوتی ہیں ان پر اجارہ داریاں قائم کرنے کی اجازت کس اصول کے تحت جائز ہے؟ زمین کی پیداوار چاہے داخلی ہو چاہے خارجی ہو، اب تو بات اس قدرتی پیداوار سے بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہر قسم کی مصنوعات ، بلاواسطہ یا بالواسطہ زمین ہی کی کسی پیداوار کا نیا روپ ہیں۔ ابھی تک انسان نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ کن فیکونکہے اور عدم سے اشیا ظہور میں آجائیں۔ اس لیے انسانی بقا اور انسانی ضروریات کو ملزوم اشیا کا دائرہ اگر مصنوعات تک بھی پھیلانا پڑتاہے تو ان پر یکساں انسانی حق تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حالیہ دور میں چینی کی مثال لے لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے تناظر میں، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی احکامات کی قانونی اور اخلاقی تفریق میں ہم آخر کب تک الجھے رہیں گے؟ اگر کسی حکم کو اخلاقی قرار دیا جاتا ہے تو اس کا منشا کیا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں استحصالی طبقہ مزید مضبوط ہو اور پساہوا طبقہ مزید خاک آلود ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلامی احکامات پر از سرِ نو غور کر کے نہ صرف قانونی و اخلاقی دائروں کی تشکیل نو کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی احکام کی مقصدیت کی تنقیح بھی انتہائی ناگزیر اور لازمی ہے۔ افسوس! ہمارے ہاں اسلامی احکام کی مقصدیت پر ابھی تک تسلی بخش کام نہیں ہوا۔ زیر نظر محاضرات بھی اس کمی کا احساس دلاتے ہیں:
’’گندم گندم ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اگر کوئی شخص گندم کا گندم سے لین دین کرنا چاہے تو وہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی قیمتی گندم فروخت کر کے ذرا معمولی قسم کی گندم زیادہ مقدار میں حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ مونٹری ایکانومی کی طرف جائے یعنی وہ پہلے سکہ رائج الوقت کے حساب سے اپنی گندم فروخت کرے۔ پھر اس نقد رقم سے جو حاصل ہو، بازار میں جتنی اور جیسی چاہے گندم خرید لے۔‘‘ (پہلا خطبہ: ص ۵۵)
ڈاکٹر غازی مرحوم نے اس اصول کے جواز اور حکمت پر تفصیلی روشنی نہیں ڈالی۔ آج کے حالات میں یہ اصول حیلہ معلوم ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ ہر چیز کی قیمت متعین ہوتی ہے، ایسے ماحول میں اچھی اور معمولی گندم کی قیمت مارکیٹ میں متعین ہو جائے تو ان قیمتوں کو پیمانہ مانتے ہوئے انہی قیمتوں کی بنیاد پر اچھی اور معمولی گندم کا تبادلہ کیوں ممکن نہیں؟ بارٹر سسٹم (اشیا کے بدلے اشیا کا تبادلہ) کے دور میں اشیا کی قیمتیں متعین نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ذرائع رسل و رسائل میں انسان کی پس ماندگی تھی جس کی وجہ سے ایک ہی علاقے میں ایک ہی شے کی مختلف قیمتیں ہوتی تھیں۔ مثلاًاگر ذرائع رسل و رسائل کی ترقی کو سمیٹ دیا جائے تو پاکستان کے مختلف شہروں میں(بلکہ ایک ہی شہر کی مختلف منڈیوں میں) ایک ہی چیز کی قیمت مختلف ہو جائے گی(اگرچہ ذہنی پس ماندگی کے باعث عملاًایسا ہی ہو رہا ہے)۔اب مواصلات کے شعبے میں حیرت انگیز ترقی نے انسانوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پوری دنیا میں کسی بھی چیز کی ایک ہی قیمت متعین کر سکتے ہیں۔ شاید مستقبل میں کبھی ایسا ہو بھی جائے، اس لیے آج کے دور میں قیمتوں کو پیمانہ بنا کر ایک ہی جنس کی شے کے تبادلے میں کمی بیشی کرنے میں معاشی اخلاقی اور شرعی اعتبار سے شاید کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ اصول ڈاکٹر محمود مرحوم کی اختراع نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ مبارک سے اخذ کردہ ہے، اس لیے اس پر نہایت سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
’’سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے، چھوارے کا چھوارے سے، نمک کا نمک سے، برابر برابر اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، اور جب یہ اصناف بدل جائیں تو جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو، لیکن یہ خرید و فروخت بھی ہاتھ در ہاتھ ہونی چاہیے۔‘‘
یہ فرمانِ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بارٹر سسٹم کے متعلق ہے۔ اب جبکہ مونیٹری سسٹم رائج ہے تو کیا اب اس حدیث پاک کو متروک سمجھا جائے؟ دیکھنے میں آیا ہے کہ معاصرین اس حدیث پاک کو عصری ماحول میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے سودی نظام کی تفہیم تک محدود کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں گنوائی گئی اشیا کی تعداد اور بارٹر سسٹم کو الگ رکھ کر، ان اشیا کی نوعیت ملحوظ رکھتے ہوئے فرمانِ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دریافت کرنے کی کوشش کی جائے تو دو معنوی پرتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اشیا انسانی ضروریات کی عمومیت پردال ہیں، یعنی ان کا دائرہ ہر دور کی ضروریاتِ زندگی کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے جسے اصطلاحاًکفاف کہا جا سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کی ضروریاتِ زندگی کے لحاظ سے اشیا کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عمومی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس حدیث پاک کی دوسری معنوی پرت یہ ہے کہ کسی زمانے میں ضروریاتِ زندگی کو ملزوم ایک ہی جنس کی شے ، اعلیٰ اور حقیر کے نام پر منقسم نہ کی جائے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی لازمی چیز مثلاًگندم چاول چینی وغیرہ، اعلیٰ ترین اور کم ترین کے نام سے مارکیٹ میں آئے گی اور زیادہ منافع کی غرض سے اعلیٰ درجے کی جنس کو رواج دینے کی کوشش کی جائے گی جس کے نتیجے میں ایک تو کفاف کے درجے میں کم ترین درجے کی جنس بھی اکثریتی آبادی کی ضروریات پوری نہ کر پائے گی اور دوسرا یہ کہ اس سے ضروریاتِ زندگی کی تکمیل میں بھی مساوات کے بجائے عدمِ مساوات قائم ہوجائے گی کہ معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ اعلیٰ ترین درجے کی جنس کا خریدار ہو گا اور اس سے ضروریاتِ زندگی کے باب میں بھی دکھاوے کی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ کفاف کے درجے میں ایسی دوڑ یا ایسی عدمِ مساوات دین اسلام کی روح سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ لہٰذا اس حدیث نبوی میں مضمر مقصدیت کو پیچھے کی سطروں میں مذکور ’’یکساں حق‘‘ کی مطابقت میں لینا، اس کی عصری معنویت سے لگا کھاتا ہے۔یہاں ضمناًیہ نکتہ پیش نظر رہے کہ آج اکیسویں صدی میں شرعی احکام کے الفاظ کی پیروی کے بجائے شریعت کے مقاصد کی تفہیم (جیسا کہ وقف، بیمہ،عاقلہ اور وینچر کیپیٹل کی بحث میں بھی مقاصد پر نظر رکھی گئی)، غالباًواحد راستہ ہے جس پر چل کر دین اسلام عملی تقاضوں کا مناسب حل پیش کر سکتا ہے اور تنفیذ کی منزل پا سکتا ہے۔ اگر الفاظ ، مقاصد کے ذرائع کے بجائے خود ہی مقصد ہیں تو پھر(مثال کے طور پر) دشمن کے خلاف جہاد میں بھی گھوڑے دوڑانے چاہییں اور تیر برسانے چاہییں۔ ڈاکٹر غازی مرحوم نے کفاف کے ضمن میں ریاستی ذمہ داری پر اس طرح روشنی ڈالی ہے:
’’ شریعت کا رجحان اور مزاج یہ ہے کہ کفاف اور ضروریات کے لیے تو ریاست کے وسائل مکمل طور پر خرچ کیے جائیں۔ حاجیات کے لیے ریاست کے وسائل وہاں خرچ کیے جائیں جہاں دستیاب ہوں اور جتنے دستیاب ہوں، اتنے ہی خرچ کیے جائیں۔ تکمیلیات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ چونکہ لامتناہی ہیں، اس لیے اگر ان پر کنٹرول نہ کیا جائے، ان کو حدود کے مطابق نہ بنایاجائے تو یہ رجحان ناپسندیدہ رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: ’’لو کان لا بن آدم وادیان من ذھب لابتغیٰ ثالثا‘‘ اگر آدم کے کسی بیٹے کے پاس دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی ہوں تووہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ خود قرآن پاک کا ارشاد ہے: ’’انہ لحب الخیر لشدید‘‘ انسان مال کی محبت میں شدید ہے۔ ...... ریاست کی اصل اور بنیادی ذمہ داری کفاف کی ہے۔ کفاف میں بنیادی اور ناگزیر طور پر تین چیزیں تو لازماًاور ہر حال میں شامل ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو لباس فراہم کرنا، بے گھر کو گھر فراہم کرنا۔ روٹی کپڑا اور مکان کی فراہمی کفاف ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کے ذمے واجب علی الکفایہ ہے۔ اس واجب کو یا فرض کفایہ کو عامۃ الناس کی طرف سے ریاست ادا کرے گی، اس لیے کہ ریاست عامۃ الناس کی وکیل ہے۔ عامۃ الناس موکل ہیں، ریاست ان کی وکیل ہے، اس لیے موکل کی طرف سے وکیل اس فریضے کو انجام دے گا۔ فقہائے اسلام میں سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، جن میں علامہ ابنِ حزمؒ کا نام بہت مشہور ہو گیا ہے کہ اگر ریاست اپنے ان تقاضوں کو پورا نہ کرے یا ریاست ان فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور کوتاہی اختیار کرے اور معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کو روزی پیٹ بھر کر نہ ملتی ہو، ایسے لوگ موجود ہوں جن کے پاس تن ڈھانپنے کو لباس نہ ہو، سر چھپانے کو چھت نہ ہو تو وہ زبردستی خود باوسیلہ لوگوں سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔‘‘(چوتھا خطبہ:ص۱۸۲،۱۸۳)
اس اقتباس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بندوق چلانا چاہتے ہیں لیکن ابنِ حزمؒ کے کندھوں پر رکھ کر ۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے علما و سکالرز کی اکثریت اس طرح کے معاملات میں طرح مصرع ملنے پر بھی غزل کہنے سے گریز کرتی ہے؟ ان کا یہ سہما سہما معذرت خواہانہ انداز شاید اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی میں سوشلزم کی مخالفت برائے مخالفت میں خود انھی مقاصد (کفاف وغیرہ) سے چشم پوشی کرتے رہے ہیں، حالانکہ خلیفہ اول نے طبقاتی کشمش کی پیش بندی کر کے مساوات اور حریتِ فکر کی راہ ہموار کر دی تھی جس کا اعتراف خود ڈاکٹر غازیؒ بھی کر رہے ہیں:
’’ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے زمانے میں جب تمام مجاہدین کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں تو سیدنا صدیق اکبرؓ نے سب کی تنخواہیں برابر رکھیں۔ ان کی اپنی تنخواہ ، ایک عام مجاہد صحابی یا تابعی کی تنخواہ کے برابر تھی۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ کمی بیشی اور اجر میں زیادتی یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ہو گی۔ دنیوی معاملات کی حد تک ہم سب کو برابر رکھیں گے ااور سب کو برابر تنخواہ دیں گے۔ اس لیے کہ معاشی ضروریات سب کی ایک جیسی ہیں۔ اہلِ خانہ سب کے ساتھ ہیں۔ کھانا پینا روزی علاج تعلیم، یہ سب کو حاصل کرنی ہے۔ اس لیے تنخواہوں میں کمی بیشی کا تصور ان کے خیال میں مناسب نہیں تھا۔‘‘ (چوتھا خطبہ: ص ۱۷۵)
سیدنا ابوبکرصدیق کے معاشی وژن کا قدرے تفصیلی ذکر ہم اپنے مضمون بعنوان’’اسلامی حکومت کا فلاحی تصور‘‘ میں کر چکے ہیں۔ (اس کے لیے فروری ۲۰۰۵ء کا ماہنامہ الشریعہ دیکھیے)۔ علامہ محمد اقبالؒ بھی اس صدیقی پالیسی سے متفق تھے۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’ملکیت، خواہ وہ جمہوریت ہی کی قبا میں پوشیدہ کیوں نہ ہو ، انسان کو فوز و فلاح سے آشنا نہیں کر سکتی بلکہ انسانی فلاح تمام انسانوں کی مساوات اور حریت میں پنہاں ہے۔‘‘ (اقبال اور قرآن از ڈاکٹر غلام مصطفی خان:ص۸۸۷)
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم بھی اس پالیسی سے ملتے جلتے رجحانات رکھتے ہیں۔ شاید اسی لیے صدرِ اسلام سے ضروریاتِ زندگی اور مفادِ عامہ سے متعلق ایک واقعہ پیش کرتے ہیں:
’’مشہور صحابی سیدنا بلال بن حارث المزنیؓ (یہ حضرت بلالؓ موذن نہیں ہیں، یہ دوسرے بلالؓ ہیں) ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب عقیق کے علاقے میں ایک بہت بڑی زمین دے دی۔ صحابہؓ نے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! اس زمین میں فلاں قسم کی پیدا وار ہوتی ہے جو عامۃ الناس کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اگر وہ ایک شخص کے پاس رہی تو شاید اس کے اثرات مناسب نہ ہوں۔ اس پر وہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واپس لے لی اور دوسری ایک زمین ان کو دے دی جس کی آباد کاری کا انہوں نے وعدہ کیا، لیکن وہ اس کو آباد نہیں کر پائے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا کہ سیدنا بلال بن حارثؓ اس زمین کو آباد نہیں کر پائے تو سیدنا عمرفاروقؓ نے ان سے وہ زمین واپس لے لی اور دوسرے مسلمانوں کو الاٹ کر دی۔‘‘ (چوتھا خطبہ :ص ۱۸۱)
نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفادِ عامہ میں زمین واپس لینا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے نہ صرف ضروریات زندگی کو ملزوم تقاضے نبھانے کی خاطر، بلکہ کسی ممکنہ اجارہ داری کے سدِ باب کے لیے بھی کسی چیز کو اجتماعی نظم میں لینے کی پوری گنجائش نکلتی ہے۔ اور رہا سیدنا عمر فاروقؓ کا طرزِ عمل تو وہ صاف صراحت کر رہا ہے کہ اسلامی احکام قانونی اطلاق کے بجائے مقصد قانون کو اصلاًاہمیت دیتے ہیں، یعنی قانونی اطلاق کی حیثیت اضافی ہے اور مقصدِ قانون اس پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی حکم کی تنفیذ کے بعد مقاصد حاصل نہیں ہوپاتے تو اس تنفیذ کی تنسیخ اس حکم کے مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہوگی۔ ڈاکٹر محمود احمد مرحوم کا درج ذیل بیان سیدنا عمر فاروقؓ کے عمل کی توضیح معلوم ہوتا ہے:
’’ ایک اہم بات وسائل کا مکمل استعمال بھی ہے۔ جس کو آج کل optimum utilization کہتے ہیں، وہ شریعت کا بھی منشا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے، جو وسیلہ عطا کیا ہے، اس کا مکمل اعتراف اور اس احسان کا مکمل اظہار ہو نا چاہیے۔ اس کی واحد شکل یہ ہے کہ اس کا استعمال مکمل ہو۔ ......اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا علم اور مہارت حاصل کی جائے کہ کسی چیز کا بہتر سے بہتر استعمال کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا گھریلو جانور جو مر جائے جس کو لوگ اس کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کسی ایسی طرح استعمال کرو اس کے مفید اجزا بالکل ضائع نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ مردہ بکری پڑی ہوئی ہے جو کسی نے پھینک دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بکری مردہ ہے اس کو پھینک دیا، لیکن اس کی کھال کو استعمال کیا جاسکتا تھا۔ دباغت کے ذریعے اس کی کھال کا چمڑا بنایا جا سکتا تھا۔ یہ چمڑا کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا جہاں چمڑا استعمال ہوتا ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ ہدایت ملتی ہے کہ کسی چیز کو بھی بغیر مکمل استعمال کے ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہے وسائل کا مکمل استعمال۔‘‘ (چوتھاخطبہ:ص۱۷۳)
لیکن یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ انسان وسائل کا مکمل استعمال کسی مثبت نتیجے کی امید پر کرتا ہے۔ ڈاکٹر غازی مرحوم نے ایک روایت پیش کی ہے جس سے اخذ ہوتا ہے کہ نتیجے کی پروا کیے بغیر انسان کو کوئی بھی مثبت عمل کر گزرنا چاہیے۔ ملاحظہ کیجیے:
’’صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس زمین ہو، کسی کے پاس زمین ہے یا تو اس میں خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو کاشت کرنے کے لیے دے دے۔ یعنی وسائل کو بغیر استعمال کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پودا لگانے کے لیے بیٹھا ہو، ہاتھ میں اس کا بیج یا قلم ہو اور ابھی لگانے کے لیے بیٹھا ہے، قیامت کا صور پھنک گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہو سکے تو اس پودے کو لگا کر پھر اٹھو اور پھر دیکھو کہ قیامت آئی ہے تو اب کیا کریں۔ فان استطاع ان لا یقوم حتی یغرسھا فلیفعل ، اگر اس کو اتنی مہلت مل جائے کہ قیامت کا صور پھونکے جانے کے بعد بھی وہ پودا لگا سکے اور پودے کو لگانے کے بعد کھڑا ہو تو اس کو ایسا کر گزرنا چاہیے۔‘‘ (پہلاخطبہ:ص۵۱)
خیال رہے مثبت عمل وہ ہوتا ہے جو فی نفسہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ اس لیے دینِ اسلام میں ایسی سرگرمی سے منع کیا گیا ہے جو اصلاًبے نتیجہ وبے ثمر ہو۔ اسی لیے خاص طور پر علم کے میدان میں بھی (نفع کے حقیقی تصورکے ساتھ) علم نافع ہی کو شریعت نے تسلیم و قبول کیا ہے۔ بقول اقبالؔ :
وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم!
کیا ہے جس کو خدا نے دل ونظر کا ندیم
وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں!
تجلیاتِ کلیم ومشاہداتِ حکیم
اس لیے اس روایت سے یہ اخذ کرنا زیادہ صحیح ہو گا کہ اگر کوئی عمل فی نفسہ نتیجہ خیز ہے، ثمرآور ہے، نفع مند ہے تو پھر انسان کو یہ سوچ کر بلکہ یہ دیکھ کر بے عمل نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کی محنت کا ثمر اسے نہیں ملے گاکہ: السعی منی والاتمام من اللہ ، کہ کوشش میرا کام ہے اورا نجام کو پہنچانا اللہ کاکام ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی مثبت سرگرمی میں مصروف رہنا چاہیے اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ نتائج و ثمرات کے حوالے سے انسان کو خود غرض اور لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ اقبالؔ نے سچ ہی کہا تھا:
جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے
حور وخیام سے گزر، بادہ وجام سے گزر!
اس روایت میں قیامت کا صور پھونکے جانے کے ساتھ پودے کا بیان محض مثال کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی ایک علامتی اہمیت بھی موجود ہے، لیکن سر دست اس علامت کی تحلیل و تشریح ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ ہمارے موضوع سے براہ راست مناسبت نہیں رکھتی۔
اپنی ذاتی منفعت کی خاطر لوگوں کو مختلف حیلوں بہانوں سے لوٹنا ایک عام انسانی روش رہی ہے۔ ڈاکٹرغازی مرحوم ایک قرآنی لفظ’’بخس‘‘ پر گفتگو کرتے ہوئے اس سے عصری تقاضوں کے موافق معنویت اس طرح اخذ کرتے ہیں:
’’ یہ بات فقہاے اسلام نے قرآن کریم کی اس آیت سے نکالی ہے جس میں ارشاد ہو اہے کہ ’’ولا تبخسوا الناس اشیاءھم‘‘ لوگوں کی چیزوں اور مال ودولت (کی قیمت) کم نہ کرو ۔ اس حکم میں بہت عموم ہے۔ لوگوں کی چیزیں اونے پونے خرید لینا، کھوٹے سکے جاری کرنا، کم وزن کے دراہم و دنانیر سے کام چلانا، کسی کی قیمتی چیز کو کم قیمت قرار دے کر خرید لینا، یہ سب بخس میں شامل ہے۔ آج کل کے لحاظ سے ہم کہ سکتے ہیں کہ سکے کو ڈی ویلیو کرنا بھی بخس کی ایک قسم ہے۔ آپ نے بطور حکومت مجھے پانچ ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا، اس کے بعد سکے کی قیمت کم کر کے آپ نے پانچ ہزار کی قیمت ڈھائی ہزار کر دی اور مجھے پانچ ہزار کا نوٹ پکڑا دیا۔ میرا استحقاق جس قیمت کا تھا، وہ قیمت آپ نے مجھے ادا نہیں کی۔ یہ بھی ’’ولا تبخسوا الناس اشیاءھم‘‘ میں شامل ہے۔ آج کل اس حکم پر عمل درآمد کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ اس حکم کو آج کی معاشی زبان میں منتقل کیسے کیا جائے؟ یہ اہل علم کے غور کرنے کا سوال ہے۔ امام احمد بن حنبل ؒ نے کم وزن کے سکے جاری کرنے کو یا جعلی طور پر چلا دینے کو فساد فی الارض قرار دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فساد فی الارض کی سزا قرآن کریم میں بہت سخت ہے۔‘‘ (چوتھا خطبہ: ص ۱۸۸)
قرآن مجید میں کم از کم تین مقامات (اعراف۷:۸۵، ھود۱۱:۸۵، شعراء۲۶:۱۸۳ ) پر بخس کی ممانعت کے ساتھ فساد فی الارض کا ذکر کیا گیاہے، اس لیے اگر یہ طے پا جائے کہ رائج الوقت کرنسی میں کسی قسم کی گڑبڑ ’’بخس‘‘ کے دئیرے میں آتی ہے تو پھر امام احمد بن حنبلؒ کا کم وزن یا جعلی سکے چلانے کے عمل کو فساد فی الارض سے تعبیر کرنا یقیناًدرست سمجھا جانا چاہیے، لیکن ہمیں حیرت ہے کہ ڈاکٹر محمو احمد مرحوم نے (روپے کے شے نہ ہوتے ہوئے بھی) اس کی قدر گرانے (devaluation) کے عمل کو تو بخس میں شمار کیا ہے، لیکن’’ محنت‘‘ اونے پونے خریدنے کو قابل غور ہی نہیں سمجھا۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبلؒ کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ ان کے دور میں محنت اونے پونے خریدنے کا عمل یا تو موجود ہی نہیں تھا یا اتنا کم تھا کہ اسے بخس کے عنوان سے فساد فی الارض میں شمار کرنا تقریباًناممکن تھا۔ ڈاکٹر غازی مرحوم چونکہ قرآن مجید کی نص سے براہ راست اخذ کرنے کے بجائے امام احمد بن حنبلؒ کے اخذ کردہ سے اخذ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آرہا ہے۔ اب ہم امام احمد بن حنبلؒ کو کہاں سے لائیں کہ وہ آج کے دور کے مطابق کچھ اخذ کریں تاکہ ہمارے سکالرز ان کے پیچھے پیچھے کچھ جھاڑ پونچھ کر سکیں! خیر! ڈاکٹر صاحب کو محنت کے استحصال کا درد تو نہیں ہے، البتہ پانچ ہزار اور ڈھائی ہزار کی مثال بتا رہی ہے کہ انہیں تنخواہ دار طبقے کی حالت زار کا نہ صرف علم ہے بلکہ وہ ان کا درد بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ وہ خود سرکاری ملازم رہے ہیں۔ حالیہ دور میں روپے کی قدر میں تیزی سے کمی، افراطِ زر میں مسلسل اضافے اور مہنگائی کے نہ رکنے والے طوفان نے ملازم اور مزدور کو ادھ موا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کیا کوئی احمد بن حنبلؒ ہے جو اسے علی الاعلان فساد فی الارض قرار دے کر امامت کا منصب سنبھال سکے؟
خیر! منفی ربا کے مانند، ہمارے دور میں بخس کا نیا روپ منفی بخس بھی سامنے آیا ہے۔ اس میں کسی کی اونے پونے قیمت والی چیز، زیادہ قیمت میں خرید لی جاتی ہے۔ حکومتوں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مثلاً ملی بھگت سے پانچ لاکھ مالیت کی زمین سرکار کے لیے ایک کروڑ میں خرید لی جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا صرف اتنا نکلتا ہے کہ سرکاری خزانے کو پچانوے لاکھ کا نقصان پہنچتا ہے اور پچانوے لاکھ کا ہی فریقین (بیچنے والے اور سرکار کی طرف سے ڈیل کرنے والے) کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یوں نفع و نقصان میں ’’برابری‘‘ کی بنیاد پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک کو جتنا نفع ہوا دوسرے کو اتنا ہی نقصان ہوا۔ اللہ اللہ خیر صلا۔ واقعہ یہ ہے کہ بددیانتی اور دھوکہ دہی بہروپیے کے مانند ہے۔ تجارت و کاروبار میں اس کے نئے نئے روپ سامنے آتے رہتے ہیں۔ قیمتوں میں مصنوعی اضافہ اس کا ایک مستقل روپ ہے۔ اس بابت ڈاکٹر محمود مرحوم فرماتے ہیں کہ:
’’جو لوگ خریداروں کو گم راہ کرنے کے لیے مصنوعی خریدار پیدا کرتے ہیں اور مصنوعی طور پر سودے کی قیمت بڑھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دھوکے باز بھی قرار دیا ہے، خائن بھی بتایا ہے اور بالواسطہ سودخور بھی قرار دیا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ خرید و فروخت منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی دھوکے کے نتیجے میں خریدار نے زیادہ قیمت لگا دی اور بازار سے زیادہ قیمت میں کوئی چیز خرید لی، ایسے کسی گم راہ کن خریدار کے قیمت بڑھانے کی وجہ سے یہ بیع بعض فقہا کے نزدیک منعقد ہی نہیں ہوتی۔ یہ باطل ہے۔ بعض دوسرے فقہا کے نزدیک یہ voidable ہے۔ اگر متعلقہ فریق چاہے تو اس کو منسوخ قرار دلوا سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث میں نجش کہا گیا ہے۔‘‘(پہلاخطبہ:ص۶۶)
آج کل خاص طور پر پراپرٹی کے معاملات میں یہ رجحان بہت عام ہے۔ تشویش ناک بات یہ ہے کہ نجش کو معاملہ فہمی کا نام دے کر اس پیشہ کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وطنِ عزیز میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز نجش کو فروغ دے رہی ہیں اور عوام الناس کو خوب لوٹ رہی ہیں، لیکن علما کی جانب سے ان کی مخالفت میں کبھی بھی آواز بلند نہیں کی گئی اور یہی علما مذہبی مسلکی نوعیت کے معاملات میں فوراًسے پہلے آستینیں چڑھا لیتے ہیں۔ اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ سماج و معاش کا مذہب سے اور مذہب کا سماج و معاش سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کا دائرۂ عمل الگ الگ ہے۔ اگر اسلام ایک ’’دین‘‘ ہے جس کے سماجی معاشی مذہبی روحانی ، غرض تمام پہلو باہم مربوط ہیں تواس کے علم برداروں کو اپنے معاشرتی مقاطعے جیسے رویے پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے ایسے رویوں پر اس طرح رائے زنی کی ہے:
’’ آج کے اہلِ علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ رائج الوقت اسالیبِ تجارت کا جائزہ لیں اور اگر ان میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی چیز شریعت سے متعارض ہے تو یہ بتائیں کہ وہ کیوں متعارض ہے اور اس تعارض کو دور کیسے کیا جائے اور اس رائج الوقت طریقے کو اسلام کے مطابق کیسے بنایا جائے۔ یہ دونوں کام انجام دینا اور اس ضرورت کی تکمیل کرنا آج کل کے علمائے کرام اور فقہا کی ذمہ داری ہے۔ کسی تجارت کو ناجائز قرار دے کر بالکلیہ نظر انداز کر دینا اور عامۃ الناس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس سے مجتنب ہو جائیں گے، یہ قابلِ عمل رویہ نہیں ہے۔ یہ طرزِ عمل نہ صحابہ کرامؓ کا تھا نہ ائمہ مجتہدین کا تھا اور نہ گزشتہ تیرہ سو چودہ سو سال کے دوران فقہائے اسلام کا یہ طرزِ عمل رہا ہے۔‘‘(چھٹا خطبہ:ص۲۴۹)
ڈاکٹر صاحب خوامخواہ اتنا خون جلا رہے ہیں، ان کے مخاطبین ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ وہ جس مٹی کے بنے ہیں، اس میں معاملہ فہمی، دور اندیشی اور واقعیت پسندی جیسی خاصیتیں پائی ہی نہیں جاتیں۔ اس مذہبی ذہن کا ایک خاص نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسی بات کا فوراًانکاری ہو جاتا ہے جو اسے تاریخی اسلام میں نہ ملتی ہو۔ دین اسلام سے وابستگی کے بجائے اس کی وفاداری تاریخی اسلام کے ساتھ استوار ہے۔ (دین اسلام اور تاریخی اسلام میں فرق دیکھنے کے لیے ماہنامہ الشریعہ نومبر۲۰۰۶ میں ہمارا مضمون بعنوان’’اسلامی تہذیب کی تاریخی بنیاد‘‘ ملاحظہ کیجیے) لیکن ڈاکٹر غازی مرحوم ’’وما علینا الاالبلاغ‘‘ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ:
’’ کسی تجارت کے جائز اور مطابقِ شریعت ہونے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ وہ سو فی صد ان فقہی طریقوں کے مطابق ہو جو فقہائے اسلام نے فقہ کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ فقہائے اسلام نے فقہ کی کتابوں میں جو طریقے لکھے ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کے زمانے میں جا بجا رائج تھے۔ فقہائے اسلام نے ان طریقوں کا جائزہ لیا، ان میں جو چیز شریعت سے متعارض نہیں تھی، اس کے تفصیلی احکام بیان کر دیے۔ جب تک ان جائز طریقوں کو شریعت کے احکام کے مطابق برتا جاتا رہا، وہ اسلامی طریقے سمجھے جاتے رہے۔ جب تجارت کے ان طریقوں کو اسلام کی تعلیم سے ہٹ کر برتا گیا تو وہ غیر اسلامی طریقے ہوگئے۔ اسی طرح آج کے تمام رائج الوقت طریقوں کو اگر اسلام کے احکام کے مطابق برتا جائے گا تو وہ جائز طریقے ہوں گے۔ اسلام کے احکام سے ہٹ کر ان پر عمل کیا جائے گا تو وہ ناجائز طریقے ہوں گے۔‘‘(چھٹا خطبہ:ص۲۴۸،۲۴۹)
شخصیتِ اعتباری اور محدود ذمہ داری کا اصول عملی لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ معاشرتی و ریاستی نظم کی نوعیت متعین کرتا ہے۔ زیرِ نظر محاضرات میں ڈاکٹر غازی مرحوم نے اس پر بھی گفتگو کی ہے، ملاحظہ کیجیے:
’’مشہور فقیہ اور صفِ اول کے قانون دان استاذ مصطفی احمد زرقا کا خیال تھا کہ شخصیتِ اعتباری کا تصور فقہ اسلامی میں پہلے دن سے موجود ہے۔ وہ اس کے لیے بیت المال اور وقف کی مثال دیا کرتے تھے کہ وقف کے متولی کی ذمہ داری وقف کی ذمہ داریوں تک محدود ہوتی ہے، اس کی ذات تک ممتد نہیں ہوتی۔ اسی طرح بیت المال کے متولی کی ذمہ داری بیت المال کے اموال تک محدود ہے، اس کی ذات تک اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مثلاًاگر بیت المال کے متولی نے بیت المال کے لیے کوئی قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ بیت المال ادا نہیں کر سکا تو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے قرض خواہوں کو متولی کی ذاتی جائیداد پر نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں متولی کی ذمہ داری بیت المال کے اموال تک محدود ہے اور اس معاملے تک محدود ہے جو اس نے بیت المال کے لیے کیا ہے۔ یہ حکم واضح طور پر شخصیتِ اعتباری اور محدود ذمہ داری دونوں تصورات پر مبنی ہے۔ بیت المال کی شخصیت متولی کی شخصیت سے الگ سمجھی جاتی ہے۔ آج ایک شخص متولی ہے، کل دوسراشخص متولی ہوگا، لیکن بیت المال کے معاملات بیت المال کے حقوق بیت المال کی آمدنی، کرایہ وصول کرنا، یہ معاملات متولی انجام دیا کرتا تھا۔ اس لیے ایک سطح پر شخصیتِ اعتباری کا تصور بھی موجود ہے اور محدود ذمہ داری کا تصور بھی موجود ہے۔ یہ دورِ جدید کے غالب فقہا کی رائے ہے۔ بعض حضرات اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ چنانچہ شام کے مشہور صاحبِ علم اور فقیہ شیخ سعید رمضان البوطی کی رائے میں شخصیتِ اعتباری اور محدود ذمہ داری کا فقہ اسلامی میں کوئی تصور نہیں۔ ان کی رائے میں یہ دونوں تصورات فقہ اسلامی کے لیے نا قابلِ قبول ہیں۔‘‘(گیارھواں خطبہ:ص۴۰۷،۴۰۸)
ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح فزیبلٹی رپورٹ اور وعدوں کی بحث میں فقہ حنفی کے بجائے بوجوہ فقہ مالکی سے مدد لی گئی ہے، اسی طرح قانون دان استاذ مصطفی احمد زرقا کے موقف کی مکمل حمایت کے بجائے شام کے فقیہ شیخ سعید رمضان البوطی کی رائے پر بھی نظر رکھی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر غازی مرحوم نے شیخ سعید رمضان البوطی کے دلائل نقل نہیں کیے، اس لیے کسی کے حق یا مخالفت میں رائے زنی مناسب معلوم نہیں ہوتی ۔ البتہ اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ محدود ذمہ داری اصل میں غیر ذمہ داری ہے۔ جدید دور کے معاشی معاملات کی پیچیدگیوں کے باعث کوئی صاحب محدود ذمہ داری کی آڑ میں بآسانی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ایسے مظاہرے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ حالیہ حج سکینڈل کو ہی لے لیجیے۔ سورۂ توبہ کی آیت۱۰۵ پر غور کیا جائے تو صاف اور واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ذاتی انفرادی معاشرتی اور ریاستی یعنی (اخلاقی، قانونی، عدالتی) غرض ہر اعتبار سے جواب دہی کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے:
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللّٰہُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُہُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَی عَالِمِ الْغَیْْبِ وَالشَّہَادَۃِ فَیُنَبِّءُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبۃ ۹:۱۰۵)
’’اور آپ کہہ دیجیے کہ عمل کرو۔ اب تمہارے عمل دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول اور مومنین۔ اور ضرور تم کو اس کی طرف پلٹنا ہے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا ۔‘‘
سورت توبہ کی اس آیت میں (فَسَیَرَی) کی نسبت اللہ اور اس کے رسول تک نہیں ہے بلکہ مومنین کو اس نسبت میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف محدود ذمہ داری میں ’’محدود‘‘ کی تلافی کے لیے ’’جواب دہی‘‘ کے موثر نظام کے قیام کی غرض سے بلکہ فزیبلٹی رپورٹ کو قابلِ مواخذہ بنانے کے لیے بھی یہ آیت شرعی جواز فراہم کرتی ہے۔ خیال رہے کہ وطن عزیز میں قومیائے گئے ادارے اور صنعتیں محدود ذمہ داری کی ہی بھینٹ چڑھی ہیں اور اشتراکی نظام کے عملی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ اسی نوعیت کا رہا ہے۔ اس لیے شخصیت اعتباری و محدود ذمہ داری اور جواب دہی کے امتزاج سے اگر کوئی نیا عملی اور موثر نظام وضع کیا جائے تو نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کی بھی عظیم خدمت ہوگی۔
اگر وسائل رزق اور مال و اسباب نا اہلوں کے ہاتھ آ جائیں تو ایسی معاشی ابتری جنم لیتی ہے جس کی روک تھام میں کوتاہی صدیوں کی سزا دیتی ہے۔ دین اسلام کے تمام پہلوؤں کا داخلی ربط ایسے کسی متوقع معاشی و اخلاقی عدمِ توازن کو، جس کا انجام تباہی ہی تباہی ہے، بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر غازی مرحوم اسلامی تعلیمات کا ایک پوشیدہ گوشہ سامنے لاتے ہیں:
’’قرآن مجید نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر کسی وقت کوئی ایسا شخص کسی بڑی دولت کا یکایک وارث ہو جائے جو بہت بے وقوف اور بے عقل ہو، جو دولت کے استعمال کا طریقہ نہ جانتا تو اس کو اپنی دولت پر کنٹرول حاصل کرنے کی پورے طور پر اجازت نہ دی جائے۔‘‘(پہلا خطبہ:ص۴۷)
سوال یہ ہے کہ بے وقوف اور بے عقل کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی جامع بات کی ہے کہ’’جو دولت کے استعمال کا طریقہ نہ جانتا تو اس کو اپنی دولت پر کنٹرول حاصل کرنے کی پورے طور پر اجازت نہ دی جائے‘‘ ۔ یہاں دولت استعمال کرنے کا طریقہ نہ جاننے کی توضیح و تشریح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دولت کے استعمال کے دوبڑے پہلو ہیں: (۱) کاروبار وغیرہ کرنا، (۲) خرچ کرنا۔ لہٰذا اگر کسی کو اس بنیاد پر بے وقوف قرار دیا جائے گا کہ وہ دولت استعمال کرنے کے طریقے نہیں جانتا تو ان دو پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ آج وطن عزیز میں ایسے دولت مند پائے جاتے ہیں جن کے کاروبار اور اخراجات انہیں بآسانی بے وقوفوں میں شامل کرا دیتے ہیں۔ جہل فی نفسہ اور جہل بالاحکام ، غرض ہر حوالے سے ان کا طرزِ عمل بے عقلی اور حماقت پر مبنی ہوتا ہے۔ شریعتِ اسلامی کا یہ پہلو جس کی تنفیذ سے فوری نوعیت کے معاشرتی و معاشی ثمرات حاصل ہوسکتے ہیں، مسلمانوں کے روایتی لٹریچر میں ’’حجر‘‘ کے عنوان سے موجود ہے۔ اس پر ایک وقیع مضمون ’’الحجر۔۔حجر کی لغوی شرعی تحقیق‘‘ مولانا سعیدالرحمن علوی مرحوم نے لکھا ہے جو ان کی کتاب ’’اسلامی حکومت کا فلاحی تصور‘‘ میں شامل ہے۔ مولانا مرحوم لکھتے ہیں کہ:
’’ امام مالکؒ ، امام ابویوسفؒ ، امام محمد بن شیبانیؒ اور امام شافعیؒ جیسے متقین اور اسلامک لا کے ماہرین ایک مسرف و مبذر پر پابندی کی بات کرتے ہیں اور ہیئت انتظامیہ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایسے شخص پر تصرفاتِ مالیہ کے سلسلہ میں رکاوٹ و پابندی عاید کرے تو ظاہر ہے کہ اسی لیے ہے کہ مال و دولت کا ضیاع نہ ہو، کچھ لوگوں کے حقوق تلف نہ ہوں اور معاشرہ میں فساد و بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ان ائمہ کے نزدیک وہ قرض دار بھی حجر کی زد میں آتا ہے جو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنی جائیداد بیچنے سے انکار کرتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت ان لوگوں کے حالات پر سنجیدگی سے غور کرے جو بینکوں سے لاکھوں کروڑوں کے قرض لے کر پلازے اور صنعتی پلاٹ وغیرہ بنا کر جائیداد بناتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب بینک ان سے واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بینکوں کو عدالتی حکمِ امتناعی کے چکر میں الجھا کر الٹا مزید نقصان کرتے ہیں اور اس طرح اسٹیٹ اور رعایا کا بے حد نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اللے تللے اڑاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ائمہ اس شخص کو بھی حجر کا مستحق گردانتے ہیں جو مختلف النوع قومی ذمہ داریوں یا قرض کی ادائیگی سے بچنے کی غرض سے جائیداد کے جعلی انتقال کرتا پھرے اور صرف ذمہ داریوں سے بچنے کی غرض سے انہیں اِدھر ادھر کر دے۔ یہ صورتِ حال بھی بڑی نازک ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں جہاں ایک خاص طبقہ ملک کی غالب جاگیر و جائیداد پر ہی مسلط نہیں بلکہ انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ اور دوسرے ہر شعبہ پر اس کا کنٹرول ہے۔ یہی طبقہ اب جاگیر و جائیداد پر قبضہ سے آگے بڑھ کر تجارت و صنعت پر بھی چھا چکا ہے۔ اول تو اس کے پاس جو جاگیر ہے، وہ ہی محلِ نظر ہے کہ اس کے آبا و اجداد نے قومی مفادات کا سودا کر کے غیر ملکی سامراج اور آقاؤں سے یہ جاگیر حاصل کی۔ پھر اس نے سرکاری ٹیکسز اور الٰہی ٹیکسز(عشر وغیرہ) کی ادائیگی کی کبھی فکر نہیں کی۔ (الا ما شاء اللہ تعالیٰ) اس نے تجوریاں بھریں اور مختلف ذرائع و اسباب سے سیاست و نظم اور عدل و مقننہ پر بھی قابض ہو گیا۔ اس کی ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ وہ زکوٰۃ تک جیسے لازمی حکم سے بچنے کی غرض سے سال ختم ہونے سے چند دن پہلے اپنا سرمایہ اپنی بیوی وغیرہ کے نام منتقل کرا دیتا ہے اور اگلے سال وہ پھر اسی طرح مالک رہتا ہے اور جب کبھی حکومت اس جائیداد اور جاگیر کے حصے بخرے کرنے کا سوچتی ہے تو وہ جعلی انتقالات سے جائیداد اِدھر ادھر کر دیتا ہے۔ ایسے اشخاص پر حجر و پابندی بے حد ضروری ہے۔ ہم اپنے ملک کی مختصر تاریخ میں زرعی اصطلاحات کے نام پر تین مرتبہ (دولتانہ، ایوب، بھٹوکے ادوار) اس قسم کے جعل و فراڈ سے گز ر چکے ہیں۔‘‘ (اسلامی حکومت کا فلاحی تصور: ص ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰)
سوال یہ ہے کہ ’’حجر‘‘ کا نفاذ کون کرے گا؟ کیا اس سے متاثر ہونے والے خود یہ قدم اٹھائیں گے؟ کیا وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماریں گے؟ مال و اسباب ان کا، حکومت ان کی، ادارے ان کے اور (معاف کیجیے گا) علما بھی ان کے۔ اس کی ایک ہی عملی صورت ہو سکتی ہے کہ درد مند حضرات یہ پیغام عامۃ الناس تک پہنچانے کی بھر پور کوشش کریں، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں، رائے عامہ ہموار کریں اورخاص طور پر مسلم تاریخ سے حجر کے اطلاق کے نظائر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں۔ ایسے دردمند حضرات کو تاویلات پیش کرنے والوں کے سامنے بھی ا چھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ بہرحال! ڈاکٹر غازی مرحوم اسراف و تبذیر کو سماجی عمومیت کے دائرے میں لاتے ہیں۔ ان کے درج ذیل نکات سے جزوی اتفاق کیا جا سکتا ہے:
’’مسلمان صارف کا رویہ غیر مسلم صارف سے مختلف بنانے کے لیے تربیت درکار ہے۔ آج کل کی پوری معیشت صارفین کے رویے کے مطالعے پر مبنی ہوتی ہے۔ بہت سی معاشی پالیسیاں صارفین کے رویوں کے مطالعے کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں۔ اگر مسلمان صارف کا رویہ غیر مسلم صارف سے مختلف نہیں ہے تو پھر اسلامی معیشت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلامی معیشت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان صارفین کا رویہ غیر مسلم صارفین کے رویے سے مختلف ہو۔ مسلمان صارف وہ ہے جو حرام اشیا کی خریداری نہیں کرتا۔ مسلمان صارف وہ ہے جو اسراف اور تبذیر کا ارتکاب نہیں کرتا۔ مسلمان صارف وہ ہے جو مثلاًفحش رسائل اور کتابیں نہیں خریدتا۔ مسلمان صارف کی ضروریاتِ زندگی نسبتاًمحدود ہوں گی۔ مسلمان صارف دھوکہ دہی نہیں کرے گا۔ یہ چند مثالیں ہیں جن کے ذریعے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان صارف کا رویہ غیر مسلم صارفین کے رویہ سے کیسے مختلف ہو گا۔‘‘ (بارھواں خطبہ: ص ۴۵۲، ۴۵۳)
سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو مسلم صارفین کو اسراف، دھوکہ دہی، حرام خوری وغیرہ کی ترغیب دینے کا باعث بنے جس کے نتیجے میں اسلامی معیشت ایک خواب بن کر رہ جائے، اس کے خلاف معیشت اسلامی کے مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ’’حجر‘‘ کے عنوان سے سخت کارروائی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ڈاکٹرمحمود مرحوم خود فرما رہے ہیں کہ آج کی پوری معیشت صارفین کے رویے کے مطالعے پر مبنی ہے ، اس لیے موجودہ حالات میں حجر کی معنوی توسیع کی اور اس کے نفاذ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔
مغربی دنیا کے استحصالی اقدامات ڈاکٹر غازی مرحوم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ بھر پور احساس رکھتے ہیں کہ مغربی اقوام کی ترقی، مشرقی اقوام بالخصوص مسلمانوں کی ضروریاتِ زندگی اور عزتِ نفس کی قیمت پر ہوئی ہے۔ افراطِ آبادی پر مسلم موقف کی موثر ترجمانی کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا کے موقف کا تنقیدی جائزہ ڈاکٹر محمود مرحوم نے اس طرح لیا ہے:
’’ دوسری طرف یہ امرِ واقعہ ہے جس سے قرآن و سنت کا کوئی طالب علم انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کا رجحان کثرتِ آبادی کی طرف ہے، بشرطیکہ کثرتِ آبادی کسی فرد کے لیے ذاتی طور پر غیر عملی ثابت نہ ہو۔ شریعت نے نکاح کو سنتِ موکدہ قرار دیا، ازدواجی زندگی کو مجرد زندگی سے بہتر اور افضل قرار دیا۔ ......جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تھے، وہ سب کے سب متاہلانہ زندگی گزار کر گئے ہیں اور ازواج و اولاد کے تمام جھمیلے انہوں نے برداشت کیے۔ .......یہاں تعداد اور آبادی کی کثرت کا مطلب کیفیت کی قیمت پر کمیت میں اضافہ نہیں ہے۔ بلکہ کیفیت کے ساتھ ساتھ کمیت میں بھی اضافہ مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ کیفیت میں اضافہ کے لیے تو پورے قرآن کریم اور احادیث کے دفتر موجود ہیں جہاں بہتر سے بہتر اخلاق، بہتر سے بہتر ایمان ، بہتر سے بہتر کردار، بہتر سے بہتر کارکردگی، بہتر سے بہتر فکری اور تعلیمی ترقی کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ کمیتی اعتبار سے بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغربی دنیا نے محض اپنی تحسینیات اور کمالیات کی خاطر دنیا کی ضروریات و حاجیات کو قربان کرنے کا وطیرہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کنٹرول میں رہے تاکہ جو درجہ کمالیات اور تحسینیات کا ان کو حاصل ہے، وہ حاصل رہے۔ اس میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ کوئی انہیں compete کرنے والا نہ ہو اور کسی ملک کی آبادی اس حد تک نہ جائے جو ان کے لیے خطرہ ہو سکے۔‘‘ (تیسرا خطبہ:ص۱۴۹)
مسلم ممالک کی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے آنے والی غیر ملکی امداد کو ڈاکٹر غازی مرحوم شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے خبر دار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
’’یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ دنیائے اسلام کے کسی ملک کے لیے آبادی میں کنٹرول کے باب میں کبھی امدا د کی کمی نہیں ہوئی۔ مختلف ملکوں پر مختلف پابندیاں لگتی رہتی ہیں، پاکستان بھی ان پابندیوں کا شکار رہا ہے ، لیکن بدترین سے بدترین ادوار میں بھی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے باہر سے کبھی امدا دمیں کمی نہیں آئی ۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے جواب پر غور کیا جائے تو بہت سے نکتے واضح ہو جاتے ہیں۔‘‘ (تیسرا خطبہ:ص۱۵۰)
اگر اعدادو شمار دیکھے جائیں تو ڈاکٹر محمود مرحوم کی بات سے اختلاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت مسلم ممالک کی شرح پیدایش مغربی ممالک سے کہیں زیادہ ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں نوجوانوں کی تعداد میں نسبتاًمسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو قوم کی رگوں میں تازہ خون بن کر دوڑتے ہیں اور قوم کو منزل آشنا کرتے ہیں۔ بہرحال! ڈاکٹر غازی مرحوم کی تلخ نوائی جاری ہے۔ خواتین کے حقوق کو آج کل جس طرح ایشو بنایا گیا ہے، اس کے تارو پود بکھیرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
’’ یہ بات آپ کو حیرت انگیز معلوم ہو گی کہ آپ نے آج تک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر خواتین کے کسی بھی پلیٹ فارم کو یہ اعتراض کرتے نہیں سنا ہو گا کہ Primogeniture کا اصول خواتین کے حقوق کے منافی ہے۔ پوری جائیداد سب سے بڑے بیٹے کو یا سب سے بڑے پوتے کو یا سب سے بڑے بھائی کو کیوں چلی جائے؟ خواتین کو کیوں نہ ملے؟ اس پر آج تک کسی خاتون نے کسی تنظیم نے خواتین کے حقوق کے علم برداروں میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ یہاں خواتین مکمل طور پر محروم ہیں۔ مرد بھی محروم ہیں۔ صرف ایک شخص دولت کا وارث بن رہا ہے۔ اس کے برعکس شریعت پر آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ عورت کا حصہ بعض صورتوں میں آدھا کیوں ہے؟ حالانکہ جن صورتوں میں عورت کا حصہ آدھا ہے، ان میں اور بقیہ تمام صورتوں میں بھی عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری شریعت کے نظام میں نہیں ہے۔ بہرحال! قانونِ وراثت کا عملاًنافذ نہ ہونا بھی ارتکازِ دولت کے اسباب میں ہے۔‘‘(تیسراخطبہ:ص۱۴۴)
اگر مغرب میں Primogeniture کا قانون موجود ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے ہاں بھی تو خیر سے عملاً بڑے بھائی کا ہی قبضہ ہوتا ہے۔ مغرب میں تو یہ عمل پھر بھی کسی قانون ضابطے کی مطابقت میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں دھونس زبردستی سے ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط قانون رائج ہو تو اس کے خلاف دلائل کی بنیاد پر تحریک چلائی جا سکتی ہے، رائے عامہ ہموار کی جا سکتی ہے اور آخر کار اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے یا بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں قانون کے بارے میں کوئی ابہام سرے سے موجود ہی نہ ہو ، لیکن عملاًقانون کا منشا پورا نہ ہو رہا ہو تو بتائیے، وہاں بغلیں جھانکنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم Primogeniture جیسے مغربی قوانین پر تنقید سے ایک درجہ بڑھ کر ان قوانین کے پس منظر اور مغربی فکر و نظر پر بھی ڈرون حملے کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے:
’’مغرب کی پوری معیشت دن رات اسی بات کے لیے کوشاں رہتی ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کو نت نئی مادی اور شہوانی خواہشات کی آماج گاہ بنایا جائے۔ .....اسلامی شریعت اس مغربی تصور کو قبول نہیں کرتی کہ معاشی انسان سے مراد وہ زندہ وجود ہے جس کی زندگی کا مقصد وجود صرف یہ ہو کہ وہ مادی زندگی کا بہتر سے بہتر ہدف اور اعلیٰ سے اعلیٰ سطح حاصل کرے۔ حصولِ مال حصولِ زر اور حصولِ مادیات کے علاوہ اس کا کوئی محرک نہ ہو۔‘‘ (دوسرا خطبہ: ص ۹۲)
واقعہ یہ ہے کہ مذہبیات سے قطع نظر، مغرب میں اجتماعی نظم کے لیے درکار اخلاقیات بدرجہ اتم موجود ہے۔ اگر مذہبیات کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کے ہاں عموماًکرسمس جیسے مواقع پر اشیا سستی کرنے کا واضح رجحان دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں خیر سے لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اشیا سستی ہونا تو درکنار، ان کی سابقہ قیمتیں بھی برقرار نہیں رہتیں۔ اس لیے مغربی فکر کو صرف مادیت پر مبنی اور اخلاقیات سے بالکل عاری قرار دینا زیادتی اور انصاف سے روگردانی ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حصولِ مال و زر اور مادیات ہی مغربی فکر کا منشا ہے، تب بھی یہ حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ اس فکر نے ذرائع کے درجے میں سہی، لیکن انسانیت کی عملاًبڑی خدمت کی ہے۔ اس لیے ہم نہایت افسوس کے ساتھ گزارش کریں گے کہ اسلامی شریعت اگر ایسی مغربی فکر کو قبول نہیں کرتی جس نے کم از کم ذرائع کے درجے میں ہی انسانیت کی خاصی خدمت کی ہے تو کیا ہوا؟ مسلمان تو اس پر نثار ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ مسلمان اس کے آدھے حصے پر نثار ہیں یعنی حصولِ مال و زر اور مادیات پر۔ رہی انسانیت کی خدمت تو مسلمان اس سے یوں بدکتے ہیں جیسے جنگل کے کم زور جانور شیر سے بدکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ ذرائع کی اہمیت مقاصد کے تقریباًبرابر ہوتی ہے ، یعنی مقصد کے حصول کی خاطر کوئی نہ کوئی ذریعہ لازماًاختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثلاًاگر مقصد مکان کی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی ذریعے کا کام دیتی ہے۔ اب بتائیے اگر سیڑھی ہی موجود نہ ہو تو چھت پر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر مغربی فکر نے زندگی کی ماورا مادی جہت کو، ذریعے کے درجے میں رکھ چھوڑا ہے تو بہت برا بھی نہیں کیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مغربیوں سے خوامخواہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں:
’’اصطلاحات کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ بعض مغربی اصطلاحات ایسی ہیں جن سے دور دور بھی ان کا لغوی مفہوم مراد نہیں ہوتا۔ .....مثال کے طور پر ایک زمانے میں یوٹیلیٹی (utility) اور افادیت کی اصطلاحات بہت عام تھیں۔ ..... بیسویں صدی کے شروع کی دہائیوں میں بعض اہل علم ان اصطلاحات سے بہت متاثر ہوئے۔ بعض حضرات نے اپنے نام کے ساتھ افادی کا لاحقہ بھی شامل کر لیا۔ اپنے نام کے ساتھ افادی لکھنے لگے۔ .....لیکن مغربی معاشیات میں افادیت یا یوٹیلیٹی کے وہ معنی نہیں ہیں جو ان حضرات نے سمجھے۔ وہاں یوٹیلیٹی کا تصور بہت گہرا ہے جس کا تعلق فلسفہ اخلاق اور ما بعد الطبیعات سے ہے۔ پھر مغرب میں معاشی تصورات اور نظریات کے بدلنے سے افادیت کا مفہوم بدلتا رہا ہے۔ ایک زمانے میں کچھ تھا، اس کے بعد کچھ اور تھا۔ اب اس کا مفہوم خالص انفرادی مفاد کے قریب قریب ہے۔ جس چیز کو کوئی فرد اپنے خالص ذاتی مفاد کے لیے ناگزیر سمجھتا ہو، وہ اس کے لیے افادیت کی حامل ہے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے یا کسی اور پہلو سے ضرر رساں ہو۔ اسی طرح سے معقول رویہ (rational behaviour) کی اصطلاح ہے۔ (rational behaviour) یا معقول رویہ کا مفہوم لغت کی مدد سے معلوم کیا جائے گا تو اس میں کوئی چیز قابلِ اعتراض نہیں معلوم ہوگی، لیکن معاشیات کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ فرد کو اپنی ذاتی مصلحت کا زیادہ سے زیادہ حصول کرنا چاہیے اور نفع کی زیادہ سے زیادہ فراہمی کے رویے کو اپنانا چاہیے۔ یہ رویہ rational رویہ یا معقول رویہ کہلاتا ہے۔‘‘ (دوسراخطبہ:ص۸۸،۸۹)
ڈاکٹر غازیؒ نے اصطلاحات کے ضمن میں افادیت (utility) پر جو تنقید کی ہے، وہ خاصی دلچسپ ہے۔اگر ڈاکٹر غازی مرحوم مزید مثالیں پیش کرتے تو دلچسپی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اب افادیت کا مفہوم ’’خالص انفرادی مفاد کے قریب قریب ہے۔ جس چیز کو کوئی فرد اپنے خالص ذاتی مفاد کے لیے ناگزیر سمجھتا ہو، وہ اس کے لیے افادیت کی حامل ہے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے یا کسی اور پہلو سے ضرر رساں ہو‘‘۔ ان کے اس اعتراض میں یہ تضاد بیانی پائی جاتی ہے کہ ’’ مغرب میں معاشی تصورات اور نظریات کے بدلنے سے افادیت کا مفہوم بدلتا رہا ہے۔ ایک زمانے میں کچھ تھا، اس کے بعد کچھ اور تھا‘‘۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغرب میں اب تغیر کو قرار آ گیا ہے؟ کیا ان کے موجودہ افادی نظریے میں تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی؟ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ کیا ان کے افادی نظریے میں کبھی بھی اخلاقیات کی دخل اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے؟ بھئی! اگر ان کے افادی نظریے کا مفہوم بدلتا رہا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب باور کرا رہے ہیں تو مستقبل میں یہ مفہوم کیونکر نہیں بدلا جا سکے گا؟ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ ’’ مغربی معاشیات میں افادیت یا یوٹیلیٹی کے وہ معنی نہیں ہیں جو ان حضرات نے سمجھے۔ وہاں یوٹیلیٹی کا تصور بہت گہرا ہے جس کا تعلق فلسفہ اخلاق اور ما بعد الطبیعات سے ہے‘‘ تو ہم گزارش کریں گے کہ مغرب کے افادی نظریے کا فلسفہ اخلاق اور ما بعد الطبیعات سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ بات قابل بحث ہے۔ لیکن حج کا مسلمانوں کے فلسفہ اخلاق اور ما بعد الطبیعات سے بہت گہرا تعلق ہے، اس پر بحث کی گنجایش نہیں۔ تو لغت سے ہٹ کر ’’حاجی‘‘ کو جو معنی معاشرے نے دیے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ افادی کا لاحقہ ہو یا حاجی کا سابقہ، جوہر کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ بات بڑھانے کے بجائے ہم اسی بیان پر قناعت کرتے ہوئے اگلے نکتے کی طرف آتے ہیں۔
ڈاکٹر غازیؒ کو معقول رویے (rational behaviour) کے لغوی مفہوم پر اعتراض نہیں، جیسا کہ انہیں افادیت (utility) کے لغوی مفہوم پر بھی اعتراض نہیں تھا۔یہاں ان کا بنیادی اعتراض، فرد کی ذاتی مصلحت اور زیادہ سے زیادہ نفع (profit maximization) کے حصول پر ہے جسے مغرب میں معقول رویے (rational behaviour) کا نام دیا جاتا ہے۔واقعہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات وغیرہ کے مقابلے اور موازنے میں معقول (rational) کی یہ نوع اچھی خاصی غیر معقول (irrational) دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایسا ہکہ دینا ایک جذباتی سی بات ہے۔ مزہ تب ہے کہ مسلم سکالرز دلائل و براہین کے ذریعے سے مغرب پر واضح کر دیں کہ صرف ذاتی مفاد کا حصول اور تکثیر نفع، عقلی اعتبار سے اس وقت تک غیر معقول رہتے ہیں جب تک ان میں انسانی اخلاقی روحانی اقدار کو سمو نہ لیا جائے۔ اس کے لیے زندگی کی کلیت کو بھی ثابت کرنا ہو گا، نیز زندگی کے تمام پہلوؤں (معاشی سماجی ثقافتی روحانی اخلاقی مادی ما بعد الطبیعاتی وغیرہ) کے گہرے داخلی ربط کو نہایت وضاحت سے سامنے لانا ہو گا۔ لیکن مغرب کو حقیقی معقولیت (true rationalism) کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ لغت(یعنی کتابوں) میں ’’حنفی‘‘ وغیرہ کے مفہوم اور اس کی حدود کو دیکھیے، دیوبندی وغیرہ کے مفہوم اور حدود کو دیکھیے، نظری اعتبار سے یہ سب واقعی بہت معقول (rational) معلوم ہوتے ہیں لیکن عملی طور پرغیر معقولیت (irrationalism) کی انتہائی حدوں کو چھو رہے ہیں۔سچ تو یہ ہے کہ ہمارے علما نے فروعی مسائل کو معقولیت (rational) کا جامہ پہنا کر جس طرح ذاتی مصلحت اور (معاف کیجیے گا) تکثیر نفع کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مغربیوں کو صحیح معقولیت کا درس دینا تو کجا، خود مسلم سماج میں بھی معقولیت کی ترویج ناممکن ہی قرار دی جا سکتی ہے۔ ہم یہ کہنے کی جسارت نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر غازیؒ ایسے حقایق سے بالکل بے خبر رہے، البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ انہیں مغربیوں اور مغربی فکر سے خدا واسطے کا بیر لگتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں:
’’انگریزی کی ضرب المثل جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں پڑھا تھا: Honesty is the best policy ، دیانت داری بہترین پالیسی ہے۔ یعنی دیانت داری فی نفسہ بطور ایک اخلاقی قدر کے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہ فی نفسہ دیانت داری مطلوب ہے بلکہ بطور پالیسی کے اختیار کی جائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس سے مغرب کا تصور واضح ہو جاتا ہے اور مغربی ذہن کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اجتماعی اور معاشی زندگی میں اخلاقی اقدار کی اہمیت کیا ہے۔ وہ بطور پالیسی کے اگر مفید ہیں تو ان کو اختیار کرنا چاہیے اور اگر غیر مفید ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔‘‘ (دوسراخطبہ:ص۹۲،۹۳)
ڈاکٹر محمود مرحوم کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ دیانت داری کو پالیسی کیوں شمار کیا گیا ہے؟ذرا غور کیجیے کہ Policy کا عام ترجمہ حکمت عملی کیا جاتا ہے اور Honesty is the best policy کا ترجمہ ہوا: دیانت داری بہترین حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ دیانت داری کومحض مجرد تصور تک محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے زندگی کے عملی احوال کا حصہ بنانا چاہیے۔ کیا پالیسی یا حکمت عملی میں یہ خامی ہے کہ اس سے ایک مجرد تصور(دیانت داری) کو عملی زندگی کے احوال کا حصہ بنانے پر زور دیاجا رہا ہے؟ غالباًڈاکٹر صاحب ’’فقط اللہ ہو اللہ ہو‘‘ کے قائل ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی اخلاقی تصور کو ذہن نشین کرانے اور اعمال کا حصہ بنانے کے لیے یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومیؒ کی مثنوی ہی دیکھ لیجیے، اس میں اخلاقی تصورات کے ابلاغ کی غرض سے اور ان تصورات کو زندگی کے عملی احوال کا حصہ بنانے کی خاطر کیسے کیسے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر غازیؒ ، مولانا رومیؒ کو بوجوہ رعایتی نمبر دے دیں گے ، حالانکہ مثنوی کے بعض جواہر پارے حکمت عملی سے بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ بہرحال! یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں دیانت داری کو پالیسی کے طور پر بھی نہیں اپنایا گیا۔ لیکن ڈاکٹر غازی ؒ ہیں کہ مسلمانوں کی بد دیانتی پر تنقید برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں:
’’ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ دنیائے اسلام کا تاجر تو دھوکے باز ہے اور مغرب کا تاجر دھوکے باز نہیں ہے۔ دھوکہ دہی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کانفس دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنے پر اس کو آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اگر شیطان پاکستان کے تاجر کو بہکا سکتا ہے تو امریکہ کے تاجر کو بھی بہکا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ امریکہ کا تاجر شیطان کے بہکاوے سے محفوظ و مامون ہے، پاکستان کا تاجر شیطان کے وسوسوں سے محفوظ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان ممالک میں قوانین سخت ہیں۔ قوانین پر عمل درآمد کرانے والے ادارے انتہائی موثر ہیں اور رائے عامہ کے ذریعے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کے لیے ان وساوس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کام دنیائے اسلام میں بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے اور جلد سے جلد کیا جانا چاہیے۔‘‘ (آٹھواں خطبہ:ص۳۱۷)
یہ کہنا واقعی مشکل ہے کہ امریکہ وغیرہ کا تاجر شیطان کے بہکاوے سے محفوظ و مامون ہے، البتہ موازنہ کرتے ہوئے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا تاجر کسی نہ کسی درجے میں خود شیطان ضرور ہے، اس لیے یہ قوانین کی دیوار میں ایسے روزن تلاشنے میں مگن رہتا ہے جن کے ذریعے اس کی رسائی خودغرضانہ مفادات تک ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ مغرب میں قوانین پر عمل درآمد کرانے والے ادارے انتہائی موثر ہیں لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ دنیائے اسلام میں یہ ادارے انتہائی غیر موثرکیوں ہیں؟ جناب نے مغربی دنیا کے ماحول کی بات بھی خوب کی ہے لیکن دنیائے اسلام کے ’’ماحول‘‘ کے سوال پر طرح دے گئے ہیں۔ اگر دنیائے اسلام جیسا تجارتی و معاشی ماحول مغربی دنیا کا ہوتا تو ڈاکٹر صاحب اسے’’ شیطانی ماحول‘‘ کہنے سے ہرگز نہ چوکتے۔ ناطقہ سربگریباں ہے اسے کیا کہیے! لیکن ڈاکٹر غازی مرحوم احوالِ واقعی سے مکمل چشم پوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کے مزاج کی واقعیت پسندی نے ان سے یہ کہلوایا ہے کہ :
’’ہمارے یہاں کارپوریٹ کاروبار کی نگرانی کا معاملہ بہت ڈھیلا ہے۔ دنیا کے ممالک میں یہ ادارے بہت قوی، بہت کھرے اور بہت کڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ادارے نہ کھرے ہیں، نہ کڑے ہیں اور نہ تکڑے ہیں۔ نگرانی اور کنٹرول کے لیے جب تک کوئی مضبوط کھرا اور کڑا ادارہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کارپوریٹ کاروبار کا نظام مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکے گا۔ ایک اہم تجویز یہ بھی ضروری محسوس ہوتی ہے کہ اقتصادی امور سے نپٹنے کے لیے فوری عدالتیں الگ ہونی چاہییں۔ عدالتوں کے پاس کام کا انبار بہت زیادہ ہے۔ کسی جج کے لیے، وہ اعلی عدالت کا جج ہو یا ماتحت عدالت کا جج ہو، اس پورے کام سے بطریق احسن نمٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو اس کو درپیش ہوتا ہے۔ مقدمات کی کثرت کی وجہ سے ان کو جمع شدہ مقدمات کو نپٹانے کے کام میں تاخیر ہوتی ہے اورتاخیر کے نتیجے میں وہ صورتِ حال پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں، میں نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے صبرِ ایوب، عمرِ نوح اور دولتِ قارون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا ایک جزوی حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کی نگرانی میں مختلف معاملات کی الگ الگ عدالتیں قائم کر دی جائیں۔ اقتصادی امور کی عدالتیں الگ ہوں، بینکاری کی عدالتیں الگ ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ جن اسباب کی بنا پر کاروباری طبقہ پیش رفت کرنے سے گھبراتا ہے، ان رکاوٹوں کو جزوی حد تک ہی سہی، دور کیا جا سکے گا۔‘‘(بارھواں خطبہ:ص۴۴۶)
احوالِ واقعی کی بہتری کی غرض سے دی جانے والی مذکورہ تجویز نشاندہی کرتی ہے کہ ڈاکٹر محمود مرحوم جذباتیت کی رو میں بالکل ہی نہیں بہتے۔ ان میں حالات و واقعات کا معروضی جائزہ لینے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ انہی محاضرات میں یہ صلاحیت، شکوہ و شکایت کی آمیزش سے غالبؔ کے اس کہے کو عملی جامہ پہناتی نظر آتی ہے:
پر ہوں میں شکوے سے یوں، راگ سے جیسے باجا
اِک ذرا چھیڑیے، پھر دیکھیے، کیا ہوتا ہے!
ملاحظہ کیجیے کہ موصوف چھڑ گئے ہیں، لیکن قارئین کو خوب جھنجھوڑ گئے ہیں:
’’اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے جو ہم میں سے اکثرلوگوں کو یاد نہیں رہتی۔ ایک عام تاثر ہمارے ہاں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مغربیت کے دنیائے اسلام میں آنے کا واحد سبب مغربی استعمار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا بڑا سبب مسلمانوں کی اپنی کم زوریاں ہیں۔ مسلمانوں کے نظام کا ڈھیلا پن ہے۔ دنیائے اسلام میں مغربی استعمار کی آمد سے خاصا پہلے سے اسلام کے احکام پر عمل درآمد میں شریعت کی روح کے بجائے محض روایت پرستی کا جذبہ نمایاں ہونے لگا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بے جان اور کم زور روایت پرستی تیزی سے جنم لے رہی تھی جس میں نہ اسلام کی حقیقی تعمیری روح موجود تھی نہ اسلامی تہذیب کی وہ اٹھان نظر آتی تھی جو اسلامی تاریخ کے ابتدائی ایک ہزار سال میں محسوس ہوتی تھی۔ اب نہ مسلمانوں میں فکر و تہذیب میں جدت پسندی یا نئے نئے تجربات کی کوئی امنگ باقی رہی تھی اور نہ زوال و انحطاط کی اس تیزی سے پھیلتی ہوئی رَو کا زیادہ ادراک و احساس تھا۔ یہ رویہ جو خالص فکری کم زوری کا اور تہذیبی انحطاط کا غماز تھا، یہ دسویں صدی کے لگ بھگ شروع ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ادارے کم زور ہوتے گئے۔ شریعت کے احکام پر عمل درآمد کی کیفیت ظاہر پرستی کے قریب قریب پہنچ گئی اور شریعت کے مقاصد اصل اہداف اور محرکات پر توجہ دینے کے بجائے، قرآن و سنت کی ہمہ گیر اور عالم گیر نصوص پر توجہ ملحوظ رکھنے کے بجائے، بعض متاخرین کے فتاوی ہی کو شریعت کا قائم مقام سمجھا جانے لگا اور تمام معاملات مختلف علاقوں میں دنیائے اسلام کے مختلف ممالک میں رائج الوقت فقہی مسالک کے متاخر اہلِ علم کے فتاوی کے مطابق انجام دیے جانے لگے۔ شروع شروع میں تو اس غیر ضروری تقلیدی رویے کے اثرات زیادہ محسوس نہیں ہوئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے اصل مصادر یعنی قرآن وسنت سے تعلق کا احساس کم زور ہوتا چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی اس توجہ کی مستحق قرار نہ پائی جتنی توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ نظامِ تعلیم کی کم زوری اور کھوکھلے پن نے بھی ایسے علما پیدا کرنے بند کر دیے جو اس صورتِ حال میں عامۃ الناس کی موثر اور فعال مجتہدانہ رہنمائی کر سکتے۔‘‘(گیارھواں خطبہ:ص۳۹۴،۳۹۵)
بات یہ ہے کہ کل کے متاخرین آج کے متقدمین شمار ہوتے ہیں، اس لیے خواہ مخواہ کی اصطلاحات میں الجھے بغیر مسئلے کی جڑ ڈھونڈنی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ فقہی مسالک کی بے جا پیروی کا ہے۔ دین کی قانونی تعبیر پر مبنی جامد علمی رویہ اس اندھا دھند پیروی کو جواز فراہم کر رہا تھا۔ لہٰذا مسئلے کی جڑ متاخرین نہیں بلکہ دین کی کلیت کے بجائے اس کے فقہی(بمعنی قانونی) پہلوؤں پر توانائیاں صرف کر کے دینی تعبیر کو محدود کرنے والا غیر علمی رویہ تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ علما کی اکثریت ابھی تک اسی رویے سے چمٹی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک وہ اسلامی قانون جو ہزار برس قبل تشکیل پایا تھا، اس کی تنفیذہی شریعت کااصل مقصد ہے۔ خود ڈاکٹر غازی مرحوم بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی سوچ کے حامی رہے ہیں(جب وہ قرآ ن و سنت کے ساتھ متفق علیہ قواعد کو بھی دائمی قرار دیتے ہیں تو اسی فکر کی زلف کے اسیر دکھائی دیتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب قرآن و سنت کو ہی شریعت قرار دے رہے ہیں)۔ بہرحال! جہاں تک قرآن و سنت سے تعلق کی کمزوری کا تعلق ہے، یہ کمزوری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت طاقت ور ہو گئی ہے ، خاص طور پر قرآن سے تو رسمی تعلق باقی رہ گیا ہے۔ دینی مدارس کے نصاب اور طریقہ تدریس میں قرآن کو جو ’’مقام‘‘ حاصل ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس پر مستزاد کہ علماء کرام قرآن کے اسی ’’مقام‘‘ کی بقا کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی! ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم شاید رسوائی کا چرچا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے بھری بزم میں راز کی بات کہہ گئے ہیں، گستاخی و بے ادبی کے طعنے کی پروا کیے بغیر :
’’ ایک ایک کر کے دنیائے اسلام میں پہلے مغربی تصورات عام ہونے شروع ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے مغربی ادارے بھی قائم ہونے شروع ہو گئے۔ جن ممالک پر استعمار کا قبضہ براہ راست ہو گیا تھا، وہاں تو لوگ یہ کہہ کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ مغربی استعمار نے یہ سب کر دیا، لیکن جن ممالک پر براہ راست مغربی استعمار کا قبضہ نہیں ہوا یا اس وقت تک نہیں ہوا تھا، وہاں بھی اس طرح کے نئے مغربی ادارے اور نئے قوانین آنا شروع ہو گئے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس نئی تبدیلی کا اصل سبب اور محرک محض مغربی استعمار نہیں تھا بلکہ وہ خلا، وہ کم زوری اور وہ ڈھیلا پن اس کا اصل سبب تھا جو مسلمانوں کے نظام میں پیدا ہوا۔ اس کے مقابلے میں بعض ظاہر بینوں نے جب مغربی دنیا کے فعال اداروں کو، مغربی دنیا کے زندگی سے بھر پور قوانین اور اداروں کو دیکھا تو اس سے متاثر ہوئے اور ان کے دلوں میں مغربی اداروں اور قوانین کو اپنانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یوں دنیائے اسلام میں مغربی تصورات و قوانین کی طلب پیدا ہوئی۔ مغربی دنیا نے اس طلب سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ادارے، اپنے تصورات، اپنے قوانین اور اپنے طور طریقے دنیائے اسلام کو برآمد کیے۔ چنانچہ مصر میں سودی بینکوں کا آغاز ۱۸۵۵ء میں ہو گیا تھا۔ .......۱۸۵۶ء میں عثمانی حکومت نے انگریزوں کو سلطنتِ عثمانیہ میں پہلا بنک قائم کرنے کی اجازت دی۔ ....... چند سال کے اندر اندر ۱۸۶۳ء میں اس پہلے انگریزی بنک میں فرانسیسی بھی شامل ہوگئے اور اس کا نام ’’البنک السلطانی العثمانی‘‘ قرار پایا۔ گویا سلطنتِ عثمانیہ جو خلافت کا مرکز تھی، جہاں کہا جاتا تھا کہ نظامِ حکومت شریعت کے مطابق قائم ہے، جہاں شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کو انتہائی اہم مقام حاصل تھا، وہاں شیخ الاسلام اور مفتی اعظم اور دوسرے علما ئے کرام یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ آج معاشیات کی دنیا میں بینکاری کے اس نئے نظام اور بین الاقوامی تجارت کی کیا اہمیت ہے اور اس اہمیت کو نظر انداز کرنے کے نتائج کیا نکلیں گے۔ چنانچہ بنک سلطانی عثمانی قائم ہو گیا، پھر بعد میں یہی بنک ایک سرکاری فرمان کے ذریعے ترکی کا سرکاری اور مرکزی بنک قرار دے دیا گیا۔ کرنسی اور سکہ جاری کرنا اسی کا اختیار قرار پایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک خالص مغربی سودی بنک، مرکزِ خلافت میں قائم ہوا اور جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو اسی بنک کو سلطنتِ عثمانیہ کے پورے مالیاتی نظام کو وضع کرنے کنٹرول کرنے اور نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔‘‘(گیارھواں خطبہ:ص۳۹۶،۳۹۷)
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم اگر شکایت کناں ہیں تو غلط تو ہرگز نہیں ہیں۔ ملت اسلامیہ کے مرکز خلافتِ عثمانیہ کا یہ حال تھا تو باقی امہ کے احوالِ واقعی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پستی کی کس اتھاہ گہرائی میں کسمسا رہی ہو گی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ صورتِ حال جوں کی توں قائم و دائم ہے۔ الطاف حسین حالیؔ کی زبان میں:
پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے
اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے
مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد
دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے
ڈاکٹر غازی مرحوم کا شکوہ اپنی جگہ بجا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کارل مارکس کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ غالباً اس کا یہ قصور کم نہیں ہے کہ اس نے شیخ الاسلام، مفتی اعظم اور علما وفقہا کے بر عکس نہ صرف سرمایہ داری کے عفریت کو سمجھ لیا بلکہ بر وقت اسے نکیل ڈالنے کی بھی بھر پور کوشش کی۔ اگر ہم یہ نکتہ اٹھائیں کہ مرکزِ خلافت ترکی (معروف معنوں میں مذہب) سرمایہ داری کے تحفظ اور فروغ کا علم بردار بن گیا توکیا اس تاریخی تناظر سے یہ اخذ کرنا جرم ہوگا؟ تلخ نوائی جاری رکھتے ہوئے ہم گزارش کریں گے کہ اس دور کی تاریخ کا تنقیدی مطالعہ غالباًیہ حقیقت بھی آشکارا کرے گا کہ اسی دور کے کسی مسلم مستقبل بین (Muslim Futurist) نے تاریخ کے دھارے کا رخ بھانپ لیا ہو گا، لیکن اس پر ’’متجدد‘‘ ہونے کی پھبتی کسی گئی ہو گی اور وہ بے چارہ اپنا ایمان سنبھالتا رہ گیا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام کو ضابطہ حیات کہنے والے خود ساختہ ضابطہ پکڑے بیٹھے رہے اور حیات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس کا مقام ہے کہ ان پر یہ حالت ہنوز طاری ہے۔ ڈاکٹر غازی مرحوم بات بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
’’چونکہ ایک مرتبہ حکمران اور بااثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور حکمرانوں کو تجربے سے اس کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے یہاں جو روایتی قوانین یا روایتی طور طریقے چلے آ رہے ہیں، جن کو علما کرام شریعت کا حتمی تقاضا قرار دیا کرتے تھے، وہ حکمرانوں کے خیال میں نئے تقاضوں اور نئے معاملات سے عہدہ برآ ہونے میں موثر ثابت نہیں ہو رہے۔ جب یہ تصور حکمرانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا، اس وقت علمائے کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس تصور کا احساس کرتے، اس کا ادراک کرتے اور پہلے سے پیش بندی کرتے ہوئے احکامِ شریعت کی روشنی میں ایسے قوانین اور قواعد ایسے ادارے اور اصول وضع کرتے جو نئی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی موثر ثابت ہوتے اور شریعت کے احکام اور قواعد سے بھی مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتے۔ بہرحال یہ نہیں ہو سکا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہ جہاں پوری امتِ مسلمہ کی ناکامی تھی، جہاں یہ حکمرانوں کی کوتاہ اندیشی تھی، وہاں سب سے بڑھ کر یہ علمائے کرام کی ناکامی بھی تھی۔ اگر علمائے کرام اس کم فہمی اور بے بصیرتی کا مظاہرہ نہ کرتے تو شاید اس انجام سے بچا جا سکتا تھا جو پوری دنیائے اسلام کو دیکھنا پڑا۔‘‘(گیارھواں خطبہ:ص۳۹۸)
ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی علمائے کرام پر تنقید بلا جواز ہے۔ وہ بے چارے جس دینی تعبیر کے پروردہ تھے اس کے ہوتے ہوئے ان سے زمان و مکاں کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی توقع کرنا عبث ہے۔ اصل مسئلہ یا اصل کوتاہی اس دور کے علما کی نہیں جتنی ان سے قبل کے علما کی ہے، وہ علما جنہوں نے اس انجام کے لیے زمین تیار کی۔البتہ بعد کے زمانے کے علما نے مجتہد بننے کے بجائے یہی آپشن مناسب سمجھی کہ گلے میں پڑا ڈھول بجاتے رہیں۔ خیر سے یہ ڈھول اب تک بج رہا ہے، خوب بج رہا ہے اور نجانے کب تک بجتا رہے گا! اس صورتِ حال میں ہمارے ممدوحؒ نے روایتی معاشی علمی ذخیرے کو عصری تناظر میں دیکھتے ہوئے صاف صاف کہا ہے کہ:
’’آج کی ضروریات کے لحاظ سے اسلامی معیشت کا علم از سرِ نو مدون کیا جانا ضروری ہے۔ آج جس کو اسلامی معیشت یا اسلامی اقتصاد کہتے ہیں، وہ ایک بالکل نئی چیز بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ نئی اس اعتبار سے ہے کہ اقتصادِ اسلامی یا اسلامی معیشت کی اصطلاح فقہا کے یہاں موجود نہیں تھی، نہ اس فن اور عنوان سے انہوں نے فقہی احکام کو مرتب کیا۔ امام زید بن علیؒ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے زمانے سے لے کر بیسویں صدی کے اوائل تک اسلامی معیشت یا اقتصادِ اسلامی یا اسلامک اکنامکس Islamic economics کی اصطلاح فقہ کی کسی کتاب میں استعمال نہیں ہوئی تھی۔ ان موضوعات و مباحث کے لیے فقہا نے فقہ المعاملات کی اصطلاح استعمال کی ہے، مالیات، عقودِ مالیہ کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، بعض دوسری اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں۔ لیکن آج جس کو علمِ اقتصاد کہا جا رہا ہے، اس میں اور فقہ المعاملات میں مطابقت یا تطابق کی نسبت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقہ المعاملات سارا کا سارا علم اقتصادِ اسلامی ہے یا علم اقتصادِ اسلامی فقہ المعاملات سے عبارت ہے۔ ان دونوں میں اگر منطق کی اصطلاح استعمال کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہونی چاہیے۔ فقہ المعاملات کی بہت سی تفصیلات اقتصادِ اسلامی کا حصہ ہوں گی۔ اقتصادِ اسلامی کے بہت سے معاملات وہ ہوں گے جو فقہ المعاملات کی حدود سے باہر ہوں گے۔ آج جس کو ہم علم اقتصادِ اسلامی کہ رہے ہیں، وہ فقہ المعاملات کے علاوہ تصورِ مال، نظریہ مال اور کسی حد تک ان مباحث پر مشتمل ہو گا جو فقہائے اسلام کی اصطلاح میں اخلاقیات کا حصہ تھے، علم الاخلاق کا حصہ تھے، حکمت عملی کا حصہ تھے، تدبیر منزل کا حصہ تھے، سیاست مدن اور سیاست شرعیہ کا حصہ تھے۔ ان تمام موضوعات سے متعلق اس پورے مواد کو جمع کر کے جو آج کے تصورات اور تقسیم مباحث کی رو سے اقتصاد سے متعلق ہو، ایک نئے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔‘‘ (گیارھواں خطبہ: ص ۴۱۰)
اس اقتباس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمود مرحوم جدید صورتِ حال کے تناظر میں معیشت اسلامی کا احیا چاہتے ہیں۔ان کے نزدیک ’علومِ تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں‘ ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معیشت اسلامی کا احیا، زندگی کے باقی شعبوں سے کٹ کر منفرد انداز میں (بلا شرکت غیرے)ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ دین اسلام کے تمام پہلوؤں کے درمیان ایک داخلی ربط پایا جاتا ہے جو دین کی ایسی وحدت و اساس پر دلالت کرتا ہے جس کے توسط سے زندگی کے سبھی شعبے متوازی انداز میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خود ڈاکٹر غازیؒ بھی اس کے قائل ہیں۔ لہٰذا اس دینی اساس سے وابستہ ہوئے بغیر جو تمام شعبہ ہائے زندگی کو یکساں متاثر کرتی ہے، صرف اور صرف معیشت اسلامی کی بازیابی مزید مشکلات کا باعث بنے گی۔ (اس موضوع پر اصولی بحث کے لیے ہمارا مضمون’’مسلم تہذیب کی اسلامی شناخت میں قرآن و سنت کی اہمیت‘‘ ماہنامہ الشریعہ جون۲۰۰۷ میں ملاحظہ کیجیے)۔ بہرحال! مذکورہ بالا اقتباس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اقتصادِ اسلامی کے شعبے میں ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے، لیکن غازی مرحوم اپنی کشت ویراں سے مایوس نہیں ہیں۔ غالباًدل ہی دل میں’’یا رب ! یہ چنگاری بھی ہماری خاکستر میں تھی ‘‘ کہتے ہوئے، ان کی نگہِ بلند پروفیسر شیخ محمود احمد مرحوم کے عالمانہ کام پر جا ٹکی ہے :
’’ طویل غور خوض اور مطالعے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی: Man and Money جو بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کا ایک خلاصہ آکسفورڈ یونی ورسٹی پریس نے چند سال قبل شائع کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنے موضوع پر انتہائی عالمانہ اور فاضلانہ کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں تاریخ مذہب، معاشیات، فلسفہ، ریاضی، غرض ہر فن کے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ربا کی تمام قسمیں اور شکلیں وہ تمام خرابیاں رکھتی ہیں جو اسلامی معاشرے کی اساس کو مختل کرنے کے مترادف ہیں۔ میں پوری دیانت داری سے علیٰ وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر شیخ محمود احمد مرحوم کی یہ کتاب جدید اسلامی معاشیات کی تاریخ میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو امام غزالیؒ کی کتاب ’’تہافۃ الفلاسفہ‘‘ فکرِ اسلامی کی قدیم تاریخ میں رکھتی ہے۔‘‘ (ساتواں خطبہ:ص ۲۸۹، ۲۹۰)
جدید دور میں معاشیات کی اہمیت کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر غازیؒ نے اپنے ہم نام پروفیسرشیخ محمود احمد مرحوم کو ’’غزالی دوراں‘‘ کا خطاب دیا ہے۔ پروفیسر محمود مرحوم کی کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کے بیان ’’پوری دیانت داری سے علیٰ وجہ البصیرت ‘‘ پر اعتماد کرتے ہوئے اقبالی زبان میں ہم کہے بغیر نہیں رہ سکتے:
دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا
گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا!
قومی زندگی کی بقا اور ترقی مضبوط دفاع کے بغیر تقریباًنا ممکن ہے۔ قومی بجٹ کا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے فی صد دفاع کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے تو ہمارے ممدوحؒ نے کسی قسم کے شواہد پیش نہیں کیے، لیکن دفاعی بجٹ کی داخلی تقسیم کن بنیادوں پر اور کتنے فی صدی حساب سے ہونی چاہیے، اس کے لیے انہوں نے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروقؓ کے حوالے سے یہ بات گوش گزار کی ہے:
’’ ایک اور موقع پر آپؓ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک سپاہی کی تنخواہ چار ہزار درہم کر دوں گا۔ ایک ہزار درہم اس کام کے لیے کہ وہ اپنے اسلحے پر خرچ کرے ، بہتر سے بہتر اسلحہ حاصل کرے۔ ایک ہزار درہم اس کے ذاتی اخراجات کے لیے، ایک ہزار درہم اس کے گھر والوں کے اخراجات کے لیے اور ایک ہزار درہم اس کے گھوڑوں کی تیاری کے لیے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سپاہیوں کی تنخواہیں ان کی ذاتی ضروریات کے لیے بھی تھیں اور ان تمام وسائل اور ہتھیاروں کے لیے بھی تھیں جن کا بیشتر حصہ آج ریاست خود برداشت کرتی ہے۔ آج کا سپاہی اپنا اسلحہ خود فراہم نہیں کرتا۔ اپنی سواریاں خود فراہم نہیں کرتا۔ اپنی جیپ اور ٹینک خود لے کر نہیں آتا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے دفاعی بجٹ کا اگر ایک بٹا چار حصہ سپاہیوں کی تنخواہوں ، سہولیات، تیاری اور دیگر مراعات پر اور تین بٹا چار حصہ دوسرے وسائل، اسلحہ اور ہتھیاروں پر خرچ ہو تو یہ سیدنا عمرفاروقؓ کی اس پالیسی کے عین مطابق ہو گا۔‘‘(چوتھا خطبہ: ص ۱۷۸، ۱۷۹)
اگر ڈاکٹر صاحب سیدنا عمر فاروقؓ کی پالیسی کے عین مطابق چاہتے ہیں تو دفاعی بجٹ کا ایک بٹا چار نہیں بلکہ پورا نصف سپاہیوں کی تنخواہ اور گھریلو ضروریات پر خرچ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروقؓ نے دفاعی بجٹ کی جو داخلی تقسیم کی ہے، اس میں بجٹ کا نصف تنخواہوں وغیرہ میں دیے جانے سے یہ اخذ کرنا شاید درست ہو گا کہ اسلحہ وغیرہ پر بے جا رقم خرچ کرنے سے دفاع مضبوط نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت میں یہ سپاہی کی جواں مردی ہوتی ہے جو میدانِ کارزار میں کام آتی ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کرتی ہے۔ بقول مرشد اقبالؔ ، رومیؒ :
بس کناں را آں سلاح بستن بکشت
بے رجولیت چناں تیغے بمشت
گر بپوشی تو سلاحِ رستماں!
رفت جانت چوں نباشی مرد آں
’’بہت سے لوگوں کو اس ہتھیار بندی نے مروا دیا جو ہمت مردانہ کے بغیر ہاتھ میں تلوار لیے نکلتے تھے۔ بے شک تم نے بہادروں کے ہتھیار پہن لیے ہوں، لیکن ان کے چلانے کی ہمت و صلاحیت نہیں تو جان لو کہ ہتھیاربندی تمہاری جان لے لے گی۔‘‘
آج مغرب نے اربوں کھربوں ڈالر اسلحہ سازی وغیرہ میں جھونک دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے دفاع کی فکر کھائے جا رہی ہے اور خوف کے مارے اس نے اقدامی جنگیں چھیڑ رکھی ہیں۔ غالباًمغرب کے دفاعی بجٹ کا بہت کم حصہ سپاہیوں کی تنخواہوں وغیرہ کی مد میں خرچ ہوتا ہے جس سے ان کی ہمت مردانہ مزید مضمحل ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ہمت مردانہ کو صحیح زاویے سے نہیں دیکھا گیا۔ اقبالؔ کے فرمودہ ’’مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی‘‘ کو مجموعی اقبالی فکر سے کاٹ کر غلط معنی پہنا دیے گئے ہیں۔ اس کہے کا محل اور ہے اور سپاہی کی گھریلو ضروریات کی تکمیل کا محل اور ہے۔ جس طرح پیاسے کے سامنے ’’پانی پانی‘‘ دہرانے سے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، جس طرح نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کہ ہر ایک کا جدا مقام ہے، اسی طرح سپاہی کو مومن قرار دے کر اس کی ضروریات سے صرفِ نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مومن ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اب وہ فرشتہ بن گیا ہے اور انسانی واقعی ضروریات سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ فکر و سوچ کے ایسے انداز و اطوار ہمارے مجموعی سماجی رویے میں سرایت کر چکے ہیں۔ دینی مدارس کے اساتذہ کی ’’خطیر‘‘ تنخواہوں کو ہی دیکھ لیجیے۔ ان سے جس سطح کے کام کی توقع کی جاتی ہے، کیا وہ محض ’’تقویٰ‘‘ کے سہارے انجام دیا جا سکتا ہے؟ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا تقویٰ انسان کو بنیادی ضروریات سے مکمل بے نیاز کر دیتا ہے؟ یقین جانیے، اگر ایسا ممکن ہوتا تو دنیا کے اکثر و بیشتر حاکم تقویٰ پر دل و جان سے نثار ہوتے کہ محض زبانی جمع خرچ سے ان کی جان چھوٹ جاتی، اس لیے وہ ریاستی سطح پر تقویٰ کی ترویج کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا سیدنا عمر فاروقؓ کے حکیمانہ بیان کو محض سپاہیوں کی تنخواہوں تک محدود رکھنے کے بجائے زندگی کے تمام پہلوؤں تک پھیلا کر دیکھنا چاہیے۔
خیر! قومی زندگی کا ایک اور اہم پہلو دوسری اقوام کے ساتھ اختیار کیا جانے والا طرزِ عمل ہے۔ اس سلسلے میں دین اسلام عدل و انصاف، حسن سلوک اور اخوت کا درس دیتا ہے، لیکن خیر اور شر کے اس معرکے کو دیکھا جائے جو ہر انسان کے اندر برپا ہے اور جس سماج و قوم کا انسان حصہ ہے، وہاں بھی برپا ہے تو دو اقوام کے درمیان اخوت کا ’’مثالی مظاہرہ‘‘ عملی طور پر ممکن نہیں رہتا۔ ڈاکٹر غازی مرحوم قومی زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
’’حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے ہاتھ کوئی ایسی چیز فروخت نہ کی جائے جس سے کام لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل کر سکے۔ .....آج بین الاقوامی تجارت میں یہ بات پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سامان یا پیداوار جو مسلم ممالک غیر مسلم ممالک کو یا دشمنوں کو دے رہے ہیں، ان میں کون سی چیز ایسی ہے جو وہ خود مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ فقہائے اسلام نے اپنی فہم اور اس زمانہ کی صنعت کی رو سے اسلحے کی خرید و فروخت کی ممانعت کی تھی کہ محارب دشمن کے لوگوں کو اسلحہ فروخت نہ کیا جائے۔ کچھ اور فقہا نے کہا کہ اسلحہ سازی کا جو خام مال مثلاًلوہا ہے، وہ بھی فروخت نہ کیا جائے۔ جنگ کے زمانے میں گھوڑے فروخت نہ کیے جائیں۔ ڈھالیں تیر، غرض وہ چیزیں جو جنگ میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکیں، وہ دشمن کو فروخت نہ کی جائیں۔ آج کل کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھاتوں کی بعض قسمیں نہ فروخت کی جائیں۔ بعض ایسی مہارتیں نہ منتقل کی جائیں جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ انسانیت کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائیں گی۔ یورینیم نہ فروخت کیا جائے۔‘‘ (پہلا خطبہ: ص ۶۶، ۶۷)
ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ نکات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن اس امر میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن بھی اس معاملے کو خوب سمجھتا ہے۔ اس لیے مغربی ممالک سے اسلحہ خریدنے کی دوڑ میں اول آنے کے بجائے مسلم ممالک کو تکنیکی حربی و معاشی خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مغربی ممالک صرف اسی وقت اپنا اسلحہ اور تکنیک مسلم ممالک کو فروخت کرتے ہیں جب وہ اپنے لیے اس سے بہت بہتر اسلحہ بنالیتے ہیں اور تکنیکی ترقی میں بھی کئی درجے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب نے بارھویں خطبہ میں (ص ۴۵۰، ۴۵۱) اسلامی معیشت و تجارت کی پیش قدمی کے دس معیارات اشاریے (indicators) گنوائے ہیں:
۱۔ دولت کی وسیع تر تقسیم،
۲۔ چھوٹی اور گھریلو صنعتوں کا زیادہ سے زیادہ فروغ،
۳۔ مشارکہ اور مضاربہ اور ان کے تصور پر مبنی نئے طریقوں کا زیادہ سے زیادہ رواج،
۴۔ بیع مرابحہ اور تورق جیسے طریقوں کا کم سے کم استعمال،
۵۔ تجارت میں توسیع،
۶۔صنعتی ترقی میں نمایاں اضافہ اور مسلسل اضافہ،
۷۔معاشرے کے نادار طبقات کو استفادے کے مواقع کی زیادہ سے زیادہ فراہمی،
۸۔سودی معیشت میں لگی رقم کی نسبت میں کمی کا واضح رجحان،
۹۔اسلامی معیشت میں لگائے جانے والے سرمایہ میں نمایاں اضافہ کا رجحان،
۱۰۔ارتکازِ دولت میں کمی کا نمایاں رجحان۔
ہم یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ ان معیارات کا حصول آج پھر مسلمانوں کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کر سکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ معیشت و تجارت اور بینکاری کے اسلامیانے (Islamization) کے عمل کے ساتھ ساتھ اگر مذکورہ معیارات کے حصول پر کڑی نظر نہ رکھی گئی تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ استحصالی طبقہ غصے سے پھٹے پڑے مظلوم و مقہور طبقے کو اسلامیانے کا لولی پاپ (Lolly Pop of Islamization ) دے کر ٹرخا دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو نہ صرف سماج کی غالب اکثریت کے ساتھ صریحاً دھوکہ اور ظلم ہو گا بلکہ اسلام بھی قصور وار ٹھہر کر بدنامی مول لے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ معیشت کو اسلامیانے کی حکمت عملی ہمہ جہت و ہمہ رنگ ہو اور اس میں عدلِ اجتماعی کے قیام کا پورا پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ اگر اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے تو گلوبلایزیشن کے شکنجے میں جکڑی اکیسویں صدی کی ما بعدالصنعتی دنیا (post- -industrial world ) کی اکثریتی آبادی کے لیے، جو پوری طرح بے دست و پا ہو کر معاشی و اخلاقی بحران کی زد میں ہے اور کسی مسیحا کی منتظر ہے، ایسی پیش قدمی روشنی کی کرن ثابت ہو گی اور دنیا کی یہ اکثریتی آبادی اسی روشنی کو حرزِ جان بنانے کے لیے بے اختیار لپکے گی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم اس صورتِ حال سے بخوبی آگاہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی فرمودہ اقبالؔ پر انہیں یقین ہے کہ ’’تری نسبت براہیمی ہے معمارِ جہاں تو ہے‘‘۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ:
’’آج دنیا جس معاشی مشکل اور پریشانی کا شکار ہے، آج دنیا کو جو شدید معاشی بحران درپیش ہے، اس کا حل اسلامی تعلیم کے پاس موجود ہے۔ اسلامی شریعت اس بحران سے نکلنے میں دنیا کی راہنمائی کر سکتی ہے۔ یہ کام آج پاکستان کے تاجر اور کاروباری طبقے سے وابستہ حضرات کر سکتے ہیں کہ اسلام میں تجارت اور کاروبار کے جو اصول بتائے گئے ہیں، اسلامی معاشیات اور بینکاری کے جو قواعد دورِ جدید کے علما نے مرتب کیے ہیں، ان کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا جائے اور ان کی بنیاد پر ایسی کامیاب تجارتیں منظم کی جائیں جو دنیا کو اسلام کی تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ یہ سرگرمی خود ایک عبادت ہے، لیکن جب اس نیت سے کی جائے گی کہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کرنا ہے تو یہ اعلیٰ ترین درجہ کی عبادت بن جائے گی۔‘‘ (چھٹا خطبہ: ص ۲۳۶)
ڈاکٹر محمود احمدمرحوم درحقیقت اسی تصورِ عبادت کا درس دے رہے ہیں جو اس مضمون کے آغاز میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ و مطہرہ کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ اس تصورِ عبادت کی ترویج کے لیے جس درجے کی اخلاقی جرات درکار ہے، وہ طبقہ علما میں مفقود ہے۔ لیکن فطرت اپنی راہ خود نکال لیتی ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کی سچائیاں ڈھکی چھپی رہ جائیں اور اظہار کا راستہ تلاش نہ کر پائیں۔ سورۃ البلد کی آیت۴ میں ارشادِ ربانی ہے: لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ۔ لہٰذا سرگرمِ عمل رہنا، مشقت میں رہنا انسان کی فطرتِ ثانیہ ہے، اس لیے اپنے احیا کے لیے اسلام نے طبقہ علما کے تساہل سے نہیں بلکہ ہمیشہ انسان کی مشقت سے توقعات وابستہ کی ہیں۔ بقول اقبالؔ :
نقش ہیں سب نا تمام، خونِ جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام، خونِ جگر کے بغیر!
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کے محاضرات میں سے ’’محاضراتِ معیشت و تجارت‘‘ اس لحاظ سے بہت مفید ہیں کہ ان میں روایتی معاشی مباحث کو عصری اسلوب کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کہیں کہیں عصری تناظر میں دیکھنے کی کوشش بھی کئی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں ڈاکٹر غازیؒ نے ضرورت سے زیادہ احتیاط پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ ان محاضرات کا موضوع ہے جس کا فنی احاطہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تو یہ بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان محاضرات کے بین السطور ڈاکٹر غازیؒ مغربی فکر سے مخالفت برائے مخالفت کی حد تک الرجک ہیں۔ وہ اپنوں کی خامیوں کے بارے میں گول مول بات کرتے ہیں، لیکن غیروں پر ڈرون حملے کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے مثبت انداز میں لیں تو ’’عصبیت‘‘ کا نام دے کر ابن خلدون کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اسے اونٹ نگلنے اور مچھر چھاننے سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال! مجموعی طور یہ محاضرات عام قارئین اور دینی مدارس کے طلبہ کے لیے زیادہ مفید ہیں کہ ان کے توسط سے وہ نہ صرف اسلاف کے کارناموں سے واقف ہو سکیں گے بلکہ معیشت اسلامی کو درپیش جدید مسائل سے بھی کافی حد تک آگاہ ہو جائیں گے۔
تحریک سید احمد شہید رحمہ اللہ کا ایک جائزہ
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا ایک غیر مطبوعہ خطاب جسے سید محبوب الرحمن (ایل ایل ایم، اسلامک کمرشل لا، بین الاقوامی اسلامی یونیو رسٹی اسلام آباد) نے انگریزی سے اردو میں منتقل کیا۔)
بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
سید احمد شہید کی تحریک جہاد کا تذکرہ کرنے سے قبل ہم اس وقت کی تجدیدی تحریکوں کا سرسری جائزہ لیں گے جو کہ سترہویں، اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں ظہور پذیر ہوئیں۔ اگر ہم ساڑھے تین صدیوں پر محیط اس عرصہ کی تاریخ پر غور کریں تو ہم مسلم تاریخ کے اس دور میں احیا، تجدید اور اصلاح کو انتہائی واضح مقصد کے طور پر پائیں گے اور ہمیں دنیا ئے اسلام میں ہرطرف ایسے افراد، افرادکے گروہ اور تحریکیں ابھرتی ہوئی نظر آئیں گی جن کا مقصد اسلام کو، مسلم معاشر ہ میں ایک سماجی اور سیاسی محرک کے طور پر بحال کرنا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے مجدد شیخ احمد سرہندی جو کہ مجدد الف ثانی کے نام سے معروف ہیں یعنی اسلام کے دوسرے ہزار برس کے مجدد، ان سے لے کر بیسویں صدی کے آغاز تک ہمیں مسلم دنیا میں ہر جگہ کئی تجدیدی اور اصلاحی تحریکیں نظر آتی ہیں ۔اگر ہم ان تحریکوں کا بغور جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی تین قسمیں کی جا سکتی ہیں۔
پہلی قسم میں وہ تحریکیں شامل ہیں جنہیں ہم روایتی تحریکیں کہہ سکتے ہیں۔ ان تحریکوں کا بنیادی مقصد آمیزشوں اور بعد کے خارجی اضافوں سے پاک کر کے اسلام کی حقیقی اور ثابت شدہ تعلیمات کا احیا، توحید اور وحدانیت کے اصول کو اس کی سادہ اور اصلی صورت میں پیش کرنا اور تعلیمات نبو ی کی حقیقی روح اور وقار کواجاگر کرنا تھا۔ ان پہلی قسم کی تحاریک کی زیادہ دلچسپی اسی مقصدمیں تھی ۔
دوسری قسم کی وہ تحاریک تھیں جن کی نمائندگی ہندوستان میں علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خاں، مصرمیں مفتی محمد عبدہ اور دیگر علاقوں میں دوسری شخصیات کر رہی تھیں اور جو مغربی استعمار کے غلبہ کی وجہ سے ان کے افکار سے بے حد متأثر تھے۔ ان کاتصور تجدید اور نظریہ اصلا ح یہ تھا کہ مسلمانوں کو مغربی انداز فکر، مغر بی نظام تعلیم اور مغربی طریقہ کار اور مہارتوں کو اپنانا چاہیے جس سے وہ سیاسی برتری حاصل کر سکیں گے اور اس طرح وہ آخر کاراپنی کھوئی ہوئی عزت ووقار اور سابقہ حالت بحال کر پا ئیں گے۔ یہ دوسری قسم تھی۔
ان کے ساتھ ایک تیسری قسم بھی تھی جنہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں قسم کی تحریکوں کی خوبیاں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی کمزوریوں اور خامیوں سے بچا جائے۔ اس کی مثال سید جمال الدین افغانی کی مجوزہ تحریک ہے۔ سید جمال الدین افغانی بنیادی طور پر اسلامی علوم عقائد کے عالم تھے ۔ انہوں نے دنیا ئے اسلام کے متعدد سفر کیے اور انہیں مسلمانوں کو در پیش مشکلات کا براہ راست علم تھا۔ وہ عملی طور پر مسلم دنیا کے ہر حصے سے رابطہ میں تھے اوریہی وجہ تھی کہ وہ مسلم دنیا کے مسائل سے براہِ راست باخبر تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بعض مغربی ممالک کا وسیع سفر کیا اور انہیں مغربی افکار اورفلسفہ تک بلا واسطہ رسائی حاصل تھی۔ اس لیے وہ ایک ایسی تحریک کے لیے غوروفکر اور اس کے خدوخال تجویز کرنے کی بہتر پوزیشن میں تھے جو ان دونوں قسم کی تحریکوں کی خوبیوں پرمشتمل ہو اور جس سے ایک طرف آلائشوں اور اضافوں سے پاک کر کے قرآ ن وسنت کی حقیقی اور اصلی تعلیمات کے احیا کے لیے کوشش کی جائے تو دوسری طرف مغربی منہج اور مہارتوں کوان کے انداز ازِ فکر سے متأثر ہوئے بغیر ایک خاص حدتک بروے کار لایا جائے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان انتہائی باریک فرق ہے۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان مغربی طریقہ کار اور مغربی انداز فکر اور تصورات کے درمیان فرق نہ کر پاسکے۔ ہم دوسرے لوگوں کے طریق کار اور منہج کو جنہیں ہم پسند کریں، اپنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں غیر اسلامی ذرائع پر مبنی انداز فکر، نظریہ اور فلسفہ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم کسی قوم سے کچھ سیکھ رہے ہوں تو یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور اس کی گنجائش بھی ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ سے روایت کردہ حدیث میں ہے: یعمل فی الاسلام بفضائل الجاھلیۃ کہ ہم اسلام میں ان اچھے معیارات کو اپنا سکتے ہیں جو دورِ جاہلیت میں رائج تھے۔ [حدیث کے معروف اور متداول مآخذ میں ان الفاظ سے کوئی روایت موجود نہیں۔ مرتب] لہٰذا اگر ہمیں کسی جاہلی معاشرے کی کوئی اچھی چیز یا کوئی بھلائی ملتی ہے تو اسے اپنانا اور اس سے مستفید ہونا ہمارے لیے جائز ہے۔
یہ تین قسم کی تحریکیں تھیں اور تاریخی طور پر ہم انہیں بالترتیب ہی پائیں گے۔ پہلی قسم کی تحریک سب سے پہلے، دوسری قسم دوسرے نمبر پر اور تیسری قسم آخرمیں ہے۔ اگر اس تجدیدی تحریک کا جائزہ لیا جائے جس کی ابتدا سید احمد شہیدؒ نے کی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آغاز کا مسلم برصغیر کی تاریخ سے گہر ا تعلق ہے اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ اور تاریخی طاقتوں پر ایک سرسری نظر ڈالے بغیر سید احمد شہید کی اس تحریک کے حقیقی وصف کا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تفصیل میں جائے بغیر آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ برصغیر میں مسلمان نسبتاً اقلیت میں ر ہے ہیں اور جب برصغیر کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد پورا جنوبی ایشیا ہوتا ہے جس میں موجودہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، کسی حد تک برما اور افغانستان کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ یہ سب علاقے تاریخ میں برصغیر کے نام سے مشہور ہیں۔
مسلم برادری برصغیر میں ہمیشہ اقلیت کے طور پر رہی ہے، لیکن اقلیت اور کچھ علاقوں میں انتہائی اقلیت میں ہونے کے باوجود مسلمان برصغیر پر ایک ہزار سال سے زائد عرصے تک حکمرانی کرنے میں کامیاب رہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز ۹۲ ہجری میں ہوااوراس کا اختتام ۱۲۷۶ ہجری کو ہوا، لہٰذا مسلمان باوجود اقلیت ہونے کے اس وسیع علاقے پر ایک ہزار برس سے زائد عرصہ برسر اقتدار رہے۔
مسلمانوں اور برصغیر کے اصلی باشندوں کے درمیان ہمیشہ ایک شدید اور دلچسپ مخاصمت اور اختلاف رہا ہے۔ اگر آپ ہندو ثقافت اور ہندو مذہب کا مطالعہ کریں جو کہ برصغیر میں اکثریت کا مذہب اور ثقافت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مذہب اور تہذیب ہمیشہ حیرت انگیز طور پرجاذب رہی ہے کیونکہ باہر سے جتنے بھی نئے لوگ یہاں آئے، اس نے ا ن سب کو اپنے اندر ضم اور جذب کر لیا۔ اگر آپ برصغیر کی پچھلی پانچ ہزار سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ بہت زیادہ لوگوں، قوموں اور مہاجرین کو ہندوستان آتے پائیں گے جن میں ڈراو ڈینز، آریہ اور پھر مغل اور بہت سے لوگ شامل ہیں، لیکن برصغیر آنے کے فوراً بعد یہ لوگ ہندوستان کی ہندو اکثریت میں اتنی تیزی سے ضم اور جذب ہو گئے کہ خود اپنی شناخت کھو بیٹھے اور اپنی علیحدہ تہذیب، نظریہ اور نمایاں خصوصیات تک برقرار نہ رکھ سکے۔ وہ ہندو تہذیب اور ثقافت میں ضم ہوگئے اور اب انہیں ہندوؤں سے ممتاز کرنا مشکل ہو گیاہے۔ ان سب میں اگر ایک استثنا ہے تو مسلمانوں کا ہے۔
مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے انتہائی احساس، احتیاط اور ہوش مندی سے اپنے تشخص اور علیحدہ ثقافت اور نظریہ کی حفاظت کی۔ انہوں نے ہندوؤں کی نفوذ اور انضمام کی کوششوں پر مسلسل نظر رکھی۔ ان کی مسلسل کوشش اور نگرانی نے ان کے تحفظ اور برصغیر میں مسلسل ان کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ یہ مخاصمت چلتی رہی اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اس نے مختلف روپ دھارے۔ بعض اوقات ہندو خطرہ سیاسی برتری کی صورت میں پیش آیا، بعض اوقات مذہبی تحریکوں کی صورت میں اور بعض اوقات معاشرتی اصلاح کی تحریکوں کی صورت میں پیش آیا۔
اگر آپ ہندو تصور کی تاریخ سے واقف ہوں تو آپ چودھویں اور پندرھویں صدی عیسوی میں ہندو فکر میں اس تحریک کو یاد کرسکتے ہیں جو بھگتی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ ہندو بھگت برصغیر کے مختلف حصوں میں ابھرے اور ان کا مقصد دینی فلسفہ میں ایک ایسا نیا تصور پیدا کرنا تھا جو بقول ان کے مطابق برصغیر میں موجود تمام مذاہب کی اچھی خصوصیات اور خوبیوں پر مشتمل ہو۔ سکھ تحریک کا وجود میں آنا بھگتی تحریک کا براہِ راست نتیجہ تھا اور سکھ تحریک کے بانی بابا گرو نانک نے ایک نیا مذہبی فلسفہ پیش کرنے کا دعویٰ کیا جس کی بنیاد اسلام، ہندومت ، عیسائیت اور بدھ مت کی تعلیمات پر ہو۔ یہ تصور اس لیے پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس نئے فلسفہ کی طرف مائل کیا جائے تا کہ وہ ان ملتی جلتی اور مشترک چیزوں میں ضم ہو جائیں اور اپنی شناخت، اپنی علیحدہ تہذیب اور ثقافت کھو دیں، لیکن یہ تحریک جو ہندوؤں اور ہندوؤں سے ابھرنے والے دوسرے گروہ سکھوں کی تھی، مسلمانوں کو راغب کرنے میں مذہبی اور فلسفیانہ سطح پر ناکام ہوگئی لیکن سیاسی سطح پر دوبارہ سامنے آئی۔
اگر آپ مغلیہ سلطنت کے ظہور کے پس منظر سے واقف ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بڑے پیمانے پر برصغیر میں ہندو قبائل اور ہندو لوگوں کے درمیان گٹھ جوڑ ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا۔ وہ راجپوت لیڈر رانا سانگا کی قیادت میں متحد ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے اور برصغیر سے نکال باہر کرنے کی کوشش کی اور اس وقت جب مسلمان اس حالت میں نہیں تھے کہ اپنا تحفظ کرسکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسطی ایشیا سے مغلوں کو بھیجا۔ بابر اپنی فوج اور عسکری قوت کے ساتھ آیا اور رانا سانگا کو شکست دے کر دوبارہ ۳۵۰ سال کے لیے مغلیہ سلطنت قائم کر دی۔ سیاسی سطح پر اس کوشش کی ناکامی کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اندر سے ہی منتشر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ہندوستان ایک کثیر القومی ملک ہے اور اس نے سوچا کہ ہندوستان میں مختلف قومیں آباد ہیں اور یہ خیال اس کے ذہن میں ڈالا گیا کہ یہاں مسلمان، ہندومت اور بدھ مت کے پیروکار اور کچھ عیسائی بھی آباد ہیں۔ لہٰذا حکومت اور خاص طور پر بادشاہ کو ان تمام مذہبی عناصر کو یکجا کرنا اور تمام مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے قریب لانا چاہیے۔ اس طرح اسلام کو دوسرے مذہبی نظریات کے ساتھ اکٹھا کرنے کا تصور اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک فقہی قاعدہ ہے : اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (ابن نجیم، الاشباء والنظائر، ص ۱۲۱) کہ اگر حلال اور حرام اکٹھے کر دیے جائیں تو حرام غالب آئے گا یعنی حرام اور حلال کو اکٹھا کر کے جو مجموعہ بنے گا، وہ باطل ہو گا۔ اگر برائی اور اچھائی اکٹھی کر دی جائیں تو نتیجہ برائی ہی ہوگا۔ لہٰذا حق اسی صورت میں حق ہے جب خالص اور سادہ ہو اور آلودہ نہ ہوا ہو۔ اگر یہ باطل کے ساتھ آلودہ ہو جائے تو پھر یہ سارے کا سارا باطل ہوگا، پورا نظام باطل ہو گا۔ لہٰذا برصغیر میں مسلمان قائدین، مفکرین اور مسلم تجدیدی تحریکوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اسلامی نظریہ کو حقیقی ، سادہ اور غیر آلودہ رکھا جائے۔
اکبر نے ہندوؤں، ملحدین اور منحرفین کے تعاون اور مدد سے اپنا مذہبی نظریہ پیش کر کے ایک نیا مذہبی نظام متعارف کروانے کی کوشش کی جو دین الٰہی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے مطابق یہ دین الٰہی برصغیر کے تمام بڑے مذاہب کے عقائد کا مجموعہ تھا، لیکن در حقیقت یہ اسلام نہیں تھا۔ یہ کچھ بھی تھا، لیکن اسلام نہیں تھا۔ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسے ختم کرنے کے لیے وہ لوگ جو اقتدار میں تھے اور جو حلقہ حکومت کے قریب تھے، انہوں نے ایک جماعت تشکیل دی جسے فارسی میں جرگہ کہتے ہیں۔ اس جماعت کا نام ممدان اسلام یعنی اسلام کے مددگار تھا۔ یہ اسلام کے حمایتی لوگ تھے اور یہ حساس مسلم شخصیات پر مشتمل تھی۔ یہ آگے آئے اور مجدد شیخ احمد سرہندی جو مجدد الف ثانی ؒ کے نام سے مشہور ہیں، کی قیادت میں خود کو متحد کیا۔ انہوں نے اپنے ہاں سے اس ملحدانہ نظریہ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے وہ اسے ختم کرنے میں کامیاب ہوگئے اور اب یہ تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن چکا ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین الٰہی کیا تھا۔
عقلی اور مذہبی سطح پر اس تحریک کی ناکامی کے بعد ایک اور تحریک سیاسی سطح پر دوبارہ سامنے آئی۔ برصغیر میں مختلف ہندو گروہ اور قبائل پھیلے ہوئے تھے۔ اگر آپ برصغیر کے نقشے سے واقفیت رکھتے ہوں، اگرچہ میں جغرافیہ کا اچھا طالب علم نہیں، تو بر صغیر کے جنوبی حصہ پر جو گروہ غالب اور اکثریت میں تھا، وہ مرہٹوں کے نام سے مشہور تھا۔ دارالحکومت دہلی کے علاقے میں جاٹ قوم اور پنجاب میں سکھ قوم آباد تھی۔ یہ تینوں اسلام مخالف قوتیں آگے بڑھیں اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے علاقوں میں خود کو منظم کریں اور آخر کار مسلمانوں کو برصغیر سے نکال باہر کر کے اپنی برتری قائم کریں۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت کمزور تھی اور اختیارات بھی دارالحکومت اور ارد گرد کے علاقوں تک محدود تھے۔ اس کے علاوہ وہ برصغیر کے مختلف حصوں اور مختلف شہروں میں متفرق گروہوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے اور باقی ماندہ عزت و وقار کو بحال رکھنے کی کوشش میں تھے۔
مرہٹے جنوبی حصے میں، جاٹ دارالحکومت کے ارد گرد اور پنجاب میں سکھ تھے۔ سکھوں نے پنجاب کے علاقے میں سیاسی قوت و برتری حاصل کر لی کیونکہ وہ آبادی میں مناسب تعداد میں تھے۔ ان کے پاس اپنی عسکری قوت تھی اور اس کے علاوہ وہ ایک قیادت کے تحت اکھٹے اور متحد تھے، جبکہ مسلمان متفرق اور بکھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ پنجاب میں اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ یہ اٹھارہویں صدی کے اوائل میں ہو رہا تھا جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور مسلم برصغیر کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں، اجارہ داریاں اور حکومتیں قائم ہو چکی تھیں جو عملی طور پر ایک دوسرے سے مکمل طور پر خود مختار تھیں۔ یہ تینوں بڑی طاقتیں مسلمانوں کی سیاسی برتری بلکہ برصغیر سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے درپے تھیں۔ ان کا ارادہ ایک خالص ہندو بادشاہت قائم کرنے کا تھا جسے ہندو ادب میں ہندو پد بادشاہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ برصغیر میں خالصتاً ہندو بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے۔
اس مرحلہ پر شاہ ولی اللہ دہلوی آگے بڑھے۔ انہوں نے دو جہت پر کام شروع کیا۔ پہلی یہ کہ شاہ صاحب کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی تنزل کا سبب ان کی معاشرتی سطح پر انحطاط پذیری ہے اور معاشرتی زبوں حالی کی وجہ ان کی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دوری ہے کیونکہ جب تک وہ قرآن و سنت پر نظریات سے وابستہ نہیں ہوں گے، ان کا معاشرتی ڈھانچہ سلامت نہیں رہے گا اور جب تک معاشرتی ڈھانچہ سلامت نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کی سیاسی برتری اور عزت و وقار کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، چنانچہ انہوں نے اولاً اس جہت پر کام کیا اور قرآن وسنت کی تعلیمات پر مشتمل نظام تعلیم کی تنظیم نو کے لیے کوشش کی۔ انہوں نے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ کے نام سے تعلیمی ادارہ قائم کیا جس میں انہوں نے ایک اصلاح شدہ نظام تعلیم متعارف کروایا جو قرآن و سنت کی تعلیمات و احکامات پر مشتمل تھا۔ انہوں نے علما کی ایک جماعت تیار کی جنہیں انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ بعض کو سندھ، بعض کو لکھنو اور کچھ کو بنگال روانہ کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے شاگردوں کو برصغیر کے تمام حصوں میں پھیلا دیا۔
دوسری جہت پر انہوں نے قلیل مدتی اقدامات بھی کیے، کیونکہ تعلیمی انقلاب اور ایسی نسل تیار کرنے کے لیے جو مقصد اسلام کے لیے وقف ہو، ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے جو ایک طویل مدتی اقدام ہے۔چنانچہ قلیل مدتی اقدام کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کو ان تین اسلام دشمن قوتوں سے بچانے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں ان میں سے سب سے زیادہ ناقابل برداشت اور طاقتور مرہٹے تھے۔ مرہٹے تعداد میں بہت ہی زیادہ تھے، ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ وہ ایک نئے جوش اور ہمت کے ساتھ ظاہر ہوئے اور برصغیر سے مسلمانوں حتیٰ کہ اسلام کا صفایا کرنے کے درپے ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں اتنے بے رحم تھے کہ ہندؤں میں سے صحیح العقل لوگوں نے بھی ان کے وحشیانہ پن اور مسلمانوں کو دی جانے والی اذیتوں کی مذمت کی۔مرہٹوں کی حالت اس وقت یہ تھی کہ جب کہیں وہ فتح پاتے تو پورے کے پورے قصبے اور گاؤں ملیا میٹ کر دیتے، حتیٰ کہ بچوں اور عوتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے اور پورے علاقے سے زندگی کا نام ونشان ختم کر دیتے تھے۔
اس وقت افغانستان میں ایک انتہائی مستعد اور بہت اچھا مسلمان حکمران تھا جو تاریخ میں شاہ احمد درانی اور ابدالی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک اچھا مسلمان ااور پکا مجاہد اور جنگ جو تھا اور وہ شاہ ولی اللہ سے رابطہ میں تھا۔ شاہ ولی اللہ نے معاشرے کے دوسرے معززین اور قائدین کے ہمراہ شاہ احمد ابدالی سے رابطہ کیا اور ان سے برصغیر میں آکر مرہٹوں کی قوت کو ختم کرنے کی درخواست کی۔ آخر کار شاہ ولی اللہ کے قائل کرنے پر وہ اپنی عسکری قوت کے ساتھ برصغیر آیا اور دہلی کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں جو تاریخ میں پانی پت کے نام سے مشہور ہے اور دہلی سے تقریبا۱۲۰ میل کے فاصلہ پر ہے، اس جگہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان مڈ بھیڑ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے خواب کو ہمیشہ کے لیے نا ممکن بنا دیا اور صرف ایک دن میں اڑھائی لاکھ مرہٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس طرح ان کے خواب کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد مرہٹوں کی جانب سے نہ کبھی مزاحمت کا سامنا ہوا اور نہ کبھی وہ دوبارہ ابھر سکے۔ اب بھی وہ ایک کمزور قوت ہیں۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد شاہ احمد ابدالی بد قسمتی سے افغانستان واپس چلے گئے اور برصغیر میں ٹھہرنا اور قیام کرنا پسند نہیں کیا۔ اگر انہوں نے برصغیر میں ٹھہرنے اور دہلی میں اپنی قوت اورحکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہوتاتو شاید برصغیر کی تاریخ موجودہ تاریخ سے قدرے مختلف ہوتی۔ تاہم وہ واپس چلے گئے اور دہلی میں امور اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے جس طر ح وہ تھے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکھوں نے پنجاب میں برتری حاصل کر لی اور انہوں نے اسی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا جس کا آغاز مرہٹوں نے کیا تھا۔ یہ صورت حال انیسویں صدی کے آغاز میں تھی۔ شاہ ولی اللہ مرہٹوں کے خلاف اپنے منصوبے کی کامیابی دیکھنے سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے۔مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی جنگ ۱۷۶۲ء میں لڑی گئی اور شاہ ولی اللہ کا انتقال اس حتمی معرکے سے ایک سال قبل ۱۷۶۱ء میں ہوا۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز نے تحریک کی قیادت سنبھالی اور مدرسہ رحیمیہ کے مہتمم کے طور پر ان کے جانشین بنے۔ وہ اس وقت برصغیر میں ہونے والے تمام تجدیدی کاموں کے نگران تھے۔ شاہ عبد العزیز انیسویں صدی کی پہلی تہائی گزرنے کے ساتھ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت ان کی عمر اسی برس سے زائد تھی اور اس حالت میں نہیں تھے کہ مقبول تحریک کی براہ راست خود نگرانی کر سکیں اور برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی اور سیاسی وعسکری میدانوں میں مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے سے محفوظ رکھ سکیں۔ انھی وجوہ کی بنا پر انہوں نے اپنے ایک شاگرد سید احمد شہید کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ کی کاوشوں اور خاص طور پر اس تجدیدی اور اصلاحی نظریہ کو جسے شاہ ولی اللہ اور ان کے پیروکاروں نے پیش کیا، مد نظر رکھتے ہوئے جہاد کی اس مقبول تحریک کو دوبارہ شروع کریں۔
سید احمد شہید ۱۲۰۱ ہجری [نومبر ۱۷۸۶ء] میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے، لیکن بنیادی طور پر مزاج اور ذہنی رجحان کے لحاظ سے ایک مجاہد اور جنگ جو تھے، نہ کہ ایک عالم۔ اس وقت وسطی بھارت میں بھوپال نامی ایک ریاست تھی جس کی باگ ڈور ایک نیک حکمران نواب امیر خان کے پاس تھی۔ وہ ایک اچھا مسلمان تھا جس نے خود کو اسلام کے مقصد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کی سیاسی برتری کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ شاہ ولی اللہؒ کے بیٹے شاہ عبدالعزیزؒ ہدایت پر پر سید احمد شہید اس کی عسکری قوت میں شامل ہو گئے اور کچھ وقت وہاں رہے۔ یہ عرصہ جو انہوں نے نواب امیر خان کے ساتھ گزارا، کئی لحاظ سے ان کے لیے مفید رہا۔ اولاً انہوں نے برصغیر کی اہم سیاسی شخصیات سے تعلقات استوار کیے جنہیں بعد ازاں انہوں نے اپنی تحریک کی کامیابی کے لیے استعمال کیا اور ثانیاً انہوں نے جنگ جوئی اور عسکری حکمت عملی کی عملی تربیت حاصل کی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ نواب امیر خان برصغیر میں اسلام کی تجدیدی تحریک کے احیا کے لیے اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو وہ اسے چھوڑ کر دہلی واپس آگے اور شاہ عبد العزیز کو اس تمام صورت حال سے آگاہ کیا۔
شاہ عبد العزیز سے مشاورت کے بعد اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایک مقبول تحریک کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے شاہ عبد العزیز کے مدرسہ رحیمیہ کے تمام علما نے سید احمد شہید کا ساتھ دیا۔ خاص طور پر دو نہایت بزرگ علما کا تذکرہ ضروری ہے۔ ان میں ایک مولانا عبد الحئی جن کا شمار برصغیر کے علما میں انتہائی بزرگ عالم کے طور پر ہوتا ہے اور وہ شاہ عبد العزیزؒ کے داماد تھے۔ دوسرے مولانا اسماعیل شہیدؒ تھے جو شاہ عبد العزیزؒ کے بھتیجے اور شاہ ولی اللہؒ کے پوتے یعنی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ عبد الغنی ؒ کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں بزرگ علما شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالرحیم اور شاہ عبد العزیز کی قائم کردہ قدیم روایات کے نمائندے اور سب سے بزرگ ترین علما شمار کیے جاتے تھے۔ پورا برصغیر حتیٰ کہ شاہ عبد العزیز بھی انہیں قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سید احمد شہید کے حلقہ میں ان بزرگوں کی شمولیت سے اس تحریک کی شہرت اور وقار کو بہت زیادہ تقویت ملی۔
سید احمد شہید نے ان کے ہمراہ اس علاقے کا دورہ کیا جسے یو پی (United Provinces) کہتے ہیں۔ یقیناًآپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اسلامی دنوں میں ایک صوبہ لکھنؤ یا اودھ کے نام سے تھا اور وہاں ایک شہر بھی لکھنؤ کے نام سے ہے جو مولانا ابو الحسن علی الندوی کا شہر ہے۔ آپ مولانا ابو الحسن علی کی شخصیت سے واقف ہوں گے کہ وہ لکھنو میں رہا کرتا تھے۔ لکھنو کو اودھ بھی کہتے تھے۔ دوسرا صوبہ آگرہ تھا جو دہلی سے ۷۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔ ان دونوں صوبوں، آگرہ اور اودھ کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس وجہ سے علاقہ یو پی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سید احمد شہید نے یو پی کے اس پورے علاقے اور اہم شہروں اور قصبوں کا سفر کیا اور شرک و بدعات کے بارے میں اپنے نظریات کی تشہیر کی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ اس طرح لاکھوں مسلمان ان کے حلقہ میں شامل ہوگئے۔
ضروری کام مکمل کرنے کے بعد انہوں نے حج پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر آپ بحر ہند میں جہاز رانی کی تار یخ سے واقف ہوں تو جانتے ہوں گے کہ اس وقت بحر ہند برطانیہ، فرانس اور پرتگال کے جہاز رانوں کے لیے ایک جھیل کی طرح تھی اور مسلمانوں کے لیے بحر ہند میں جہاز پر سفر کرنا خطرہ سے خالی نہ تھا۔ اس بنا پر اس وقت کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حج اب فریضہ نہیں رہا، کیونکہ قرآن میں ہے: من استطاع الیہ سبیلاکہ حج اس شخص پر فرض ہے جو مکہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ چونکہ مسلمان اس حالت میں نہیں کہ مکہ جا سکیں، اس لیے حج اب فرض نہیں رہا۔ اس فاسد خیال اور رائے کو ختم کرنے کے لیے اور حج کی فرضیت کو زندہ کرنے کے لیے سید احمد شہید نے حج پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے دو یا تین سو ساتھیوں کے ہمراہ وہ اس علاقے سے بنگال کی مشرقی بندر گاہ کلکتہ تشریف لائے اور وہاں سے خلیج بنگال کے ذریعے حج کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں آپ نے ایک سال قیام کیا۔
مکہ اور مدینہ میں ایک سال کے قیام کے دوران انہوں نے اسلامی تحریکوں کے سربراہوں سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ جہاد کے مسائل اور مستقبل کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وہاں ان کا رابطہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس وقت انگریزوں اور سکھوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے عرب میں وسطی ایشیا اور افغانستان کے لوگوں سے رابطہ کیا اور آخر کار جہاد شروع کرنے کے بارے میں حکمت عملی مرتب کی۔ حج سے واپسی پر انہوں نے جہاد کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور جہادی تحریک کے مرکز کے لیے انہوں نے پنجاب کی دوسری جانب کا علاقہ جو آج کل شمال مغربی سرحدی صوبہ میں شامل ہے، منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے سات سو پیروکاروں کے ہمراہ ہجرت کرتے ہوئے پہلے نواب امیر خان کے پاس آپہنچے۔ وہاں سے سندھ اور سندھ سے قندھار کے راستے افغانستان پہنچے۔ پھر قندھار سے کابل اور کابل سے پشاور اور وہاں سے ضلع ہزارہ کے علاقے میں آئے اور اس علاقے کو انہوں نے کئی ایک وجوہ کی بنا پر اپنی جہادی تحریک کے مرکز کے طور پر منتخب کیا۔
اولاً: وہ سکھوں کی بالادستی کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ سکھوں نے مسلمانوں کو اذیتوں میں مبتلا کر رکھا تھا جبکہ وہ پنجاب میں اقلیت اور مسلمان اکثریت میں تھے۔ اگر پنجاب کو سکھوں کی بالادستی سے آزاد کروا لیا جاتا تو مستقبل میں برصغیر کے کم از کم ایک حصے یعنی سرحد میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا تھا۔
ثانیاً: سرحدی صوبہ کا علاقہ وسطی ایشیا سے ملحق تھا جہاں آبادی کے لحاظ سے مسلمان غلبے میں تھے اور پیچھے کی جانب سے انھیں مدد اور حمایت فراہم کرنے کی بہتر پوزیشن میں تھے۔
تیسرا یہ کہ تاریخی اور روایتی لحاظ سے افغانستان اور پشاور کے مسلمان پر جوش اور سنجیدہ واقع ہوئے ہیں اور برصغیر کے باقی مسلمانوں کی نسبت اسلام کے مقصد کے ساتھ ان کی وابستگی بہت زیادہ گہری تھی۔
انہی وجوہ کی بنا پر انہوں نے اس علاقے کو اپنی جہادی کاوشوں کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ یہاں علاقے پہنچے، مقامی آبادی جو مسلمانوں پر مشتمل تھی، ان کے ارد گرد اکٹھی ہوئی اور جہاد کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو پنج دھار کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخی اہمیت کی وجہ سے ہم اسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قصبے پنج دھار میں انھوں نے اپنا مرکزی ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ یہ ان کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کا دارالحکومت بھی تھا۔ سید احمد شہید نے امامت کی بیعت بھی لی اور انہیں امیر المومنین کے طور پر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے علاقے کے تمام حصوں میں قاضی اور محتسب مقرر کیے۔ اسلامی قانون کو لاگو اور شریعت کو مکمل طور رپر نافذ کیا گیا۔ ضروری تیاری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سکھوں کے خلاف عملی طور پر جہاد کا آغاز کیا۔ اگر آپ کو پشاور جانے کا اتفاق ہوا ہو تو شاید آپ نے دریائے سندھ کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا قصبہ اکوڑہ خٹک دیکھا ہو جہاں ایک بڑا دینی مدرسہ بھی ہے ۔ سید احمد شہید اور سکھوں کے درمیان پہلی مڈ بھیڑ یہاں اکوڑہ خٹک میں ہوئی۔ اس مقابلے میں مسلمان سکھوں کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے سکھوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
اس کامیابی کے بعد سید احمد شہید نے پشاور، ہزارہ اور کشمیر میں قبائلی سرداروں اور دوسرے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ اکثر نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور اس طرح عملی طور پر شمال مغربی سرحدی صوبے کا پورا علاقہ ان کے زیر اثر آگیا اور انہوں نے ہر علاقے میں اپنے قاضی اور محتسب مقرر کیے۔ لیکن ایک بات جسے تحریک کے پر جوش کارکنان کو ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے، شریعت کی بالا دستی اور اسلامی نظام قائم کرتے ہوئے جوش و جذبے میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں ر ہنی چاہیے، لیکن انہوں نے اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور مقامی لوگوں کے مقامی رواجات، مقامی روایات اور لوگوں کی پسند اور نا پسند کو مدنظر نہیں رکھا۔ ان میں کچھ لوگوں نے شریعت کو اپنانے اور قبول کرنے میں لوگوں کی صلاحیت کو اور اس بات کو مدنظر نہیں رکھا کہ وہ کس حد تک شریعت کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں اور کس حد تک اسے برداشت کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کسی پر بوجھ لادنے کی کوشش کر رہے ہوں تو آپ کو اس کی صلاحیت اور قابلیت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جب تک اس کی صلاحیت آپ کو اس بات کی اجازت نہ دے، آپ کو اس کے کندھوں پر بوجھ نہیں لادنا چاہیے۔ اس علاقے کے لوگ اس وقت شریعت کے نفاذ کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تجربہ اور تیاری نہیں رکھتے تھے۔ سید احمد کے پیروکاروں اور رفقا نے سوچا کہ یہ لوگ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ کئی صدیوں سے مسلمان ہیں اور انہیں شریعت کے نفاذ کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور خوش آمدید کہنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے کسی تدریج اور مرحلہ وار تعارف کے بغیر شریعت نافذ کر دی۔ مقامی آبادی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور خاص طور پر میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ پشاور کے اردگرد اس علاقے میں حتیٰ کہ آج بھی لوگ اپنی خواتین کے معاملات میں بڑے حساس واقع ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں شادی، طلاق اور خاندانی تعلقات کے بارے میں اپنی روایات ہیں اور خاندانی تعلقات اور خاندانی روایات کے تحفظ میں وہ بہت سخت ہیں۔ اگر کوئی فرد باہرکے دوسرے قبیلہ سے آ کر ان کی اندرونی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کرے تو اسے ہر گز برداشت نہیں کیا جاتا اور اسے بغیر کسی تامل کے آج بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔
انہی دنوں سید احمد شہید کے علم میں یہ بات آئی کہ چند خواتین جن کا تعلق بڑے خاندانوں سے ہے، ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ سید احمد شہید نے جب ان کے والدین اور سرپرستوں سے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے برابر کے مناسب رشتوں کی تلاش میں ہیں اور ایسے مناسب رشتے اور نوجوان نہیں مل رہے جن کا تعلق بڑے خاندانوں سے ہو اور دوسرے قبائل میں اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ سید احمد شہید نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی موجود مسلمان نوجوانوں اور ان کے ساتھ یو پی سے آئے ہوئے رفقا سے کر دیں۔ اس طرح ان کے اصحاب میں سے کچھ کو شادیوں میں لڑکیاں ملیں۔ اس پر ایک شدید رد عمل سامنے آیا اور یقیناًغیر اسلامی قوتوں اور اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے مخالفین نے اسے مزید بڑھاوا دیا اور اس میں مزید ایندھن بھرا اور ایک دن ان سب نے ایک مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیا اور رات کے وقت تمام مجاہدین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔
ایک رات وہ سب لوگ اپنی تلواروں، بندوقوں اور اسلحہ کے ساتھ آئے اور مسجد پر حملہ آور ہوئے۔ کچھ مجاہدین تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، انہیں قتل اور ہلاک کر دیا گیا۔ کچھ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ اپنے خیموں کی حفاظت کر رہے تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ سینکڑوں ہزاروں مجاہدین کو ایک رات میں خود مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا۔ یہ شریعت کے نفاذ کا ایک رد عمل تھا۔ اس کا مسلمانوں کے کیمپ پر ایک برا اثر مرتب ہوا، سید احمد شہید شدید دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے اس علاقے سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سوات میں ایک اچھا حکمران تھا۔ اس نے سید احمد شہید کو ہزارہ سے سوات آنے کی دعوت دی کہ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں بنائیں اور انہیں ہر قسم کی مدد اور مزید جہاد کے لیے بنیاد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ پانچ سے سات سو کے قریب مجاہدین کے ہمراہ ہزارہ سے سوات کی جانب چل دیے۔ جب وہ سوات کی جانب جا رہے تھے تو وادی کاغان کے علاقے میں ایک قصبے سے جو بالا کوٹ کے نام سے مشہور ہے، گزرے ۔ بالا کوٹ اس طرح ہے کہ اس کی ایک جانب دریائے کنہار ہے جب کہ دوسری طرف ایک بڑا پہاڑ ہے اور ان کے درمیان بالا کوٹ کا علاقہ ہے۔ سید احمد شہید اور ان کے مجاہدین نے سوات جاتے ہوئے اس علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ معلوم نہیں سکھوں، ہندوؤں، مقامی مسلمانوں یا مخالفین میں سے کسی نے سکھ فوج کویہ بات پہنچا دی کہ سید احمد شہید اپنے مجاہدین کے ہمراہ اس علاقے میں خیمہ زن ہیں اور وہ سوات کی طرف جا رہے ہیں جسے وہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے سکھوں کے خلاف جہاد شروع کریں۔
سکھ فوج پہاڑ کے اوپر کی جانب سے آئی اور یک دم بغیر کسی اطلاع کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی۔ یہ ۶؍ مئی ۱۸۳۱ء کی بات ہے، جبکہ مسلمان جنگ کے لیے قطعا تیار نہیں تھے اور انہیں اس طرف سے کسی حملے کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کے پاس ہتھیار اور اسلحہ موجود تھا اور وہ ایک ہزار کے لگ بھگ تھے۔ سید احمد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سکھوں کے حملے کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ۔ جنگ کا علاقہ اس طرح تھا کہ اس کی پچھلی جانب دریا اور سامنے کی طرف پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اوپر کی جانب سے سکھ فوج آ رہی تھی۔ آخر کار جنگ شروع ہوئی۔ سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید سب سے آگے تھے اور مجاہدین ان کے ہمراہ تھے۔ حملے کا آغاز نماز فجر کے فوراً بعد یا کچھ دیر بعد ہوا۔ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نماز ظہر سے قبل ہی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کر چکے تھے۔ باقی سینکڑوں مجاہدین کو سکھوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح جہادی تحریک کے اس مرحلے کا اختتام ہو گیا۔ یہ اس جہادی تحریک کا اختتام تھا جس کا آغاز ۱۸۲۶ء میں اور اختتام ۱۸۳۱ء میں ہوا۔ پانچ سال کو محیط اس عرصے میں وہ اپنی اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں ان کے خلاف بغاوت اور غداری ہوئی اور انہیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور پھر دوبارہ ان کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے غداری ہوئی جس کی وجہ سے انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔
مولانا اسماعیل شہید کی قبر تو معروف ہے اور ہر ایک جانتا ہے، لیکن سید احمد شہید کی میت نہ مل سکی حتی کہ ان کا سر بھی نہ مل سکا، لہٰذا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی میت کو ختم کر دیا گیا یاوہ محفوظ رہی۔ تاہم بالا کوٹ میں ایک قبر ہے جسے سید احمد شہید کی طرف منسوب کی جاتا ہے، لیکن یہ بات ثابت نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی نعش دریا میں بہہ گئی تھی اور کچھ کا خیال ہے کہ ان کی نعش تو محفوظ رہی، لیکن سر دریا میں بہہ گیا تھا۔ اس بارے میں بہت زیادہ روایات اور کہانیاں ہیں ۔ اس طرح یہ اس مرحلہ کا اختتام تھا۔ سید احمد شہید کی شہادت کے بعد ان کے جانشین اکٹھے ہوئے اور شیخ ولی محمد چلتی کو اپنا قائد منتخب کر لیا۔ اس کے بعد تحریک چلتی رہی اور وہ سوات چلے گئے اور کچھ جہاد بھی کیا، لیکن تحریک کا مرکزی اور بنیادی مرحلہ سید احمد شہید کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔
اسلام میں تفریح کا تصور
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کا ایک غیر مطبوعہ خطاب جسے حافظ آغا عبد الصمد نے مدون کیا۔)
تفریح اور خوشی اور مسرت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ موضوع ایک عمومی انداز بھی رکھتا ہے اور ایک خاص پہلو سے ہمارے لیے اہمیت بھی رکھتا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم وتربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سے معاملات میں غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہورہی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں اور الجھنیں ماضی میں پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے کہ ماضی میں اس بات کا انتظام موجود ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم وتربیت کا انتظام نہ صرف گھر سے شروع ہو، بلکہ گھر میں، بازار میں، مسجد اور مدرسے میں، دارالعلوم اور یونیورسٹی میں، کاروبار کے اداروں میں، تجارت کے مراکز میں ہر جگہ کا انتظام چوں کہ شریعت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، ہر شخص کا رویہ اور طرز عمل شریعت کے احکام کے مطابق تھا، اس لیے اس ماحول میں رہنے والا خود بخود دینی تعلیم اور دینی مزاج میں رنگ جاتا تھا۔ اس پر دینی تعلیم کا رنگ اتنا غالب آجاتا تھا کہ کسی دوسرے رنگ کو قبول کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب گزشتہ سوڈیڑھ سال کے دور انحطاط کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم ختم ہوگیا ہے، مسلم ماحول اور معاشرے سے وہ اثرات ایک ایک کرکے ختم ہوگئے جن کی وجہ سے نئے آنے والے افراد کی تربیت خود بخود ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے اب یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگوں کہ نہ صرف جزئی مسائل کی تعلیم دی جائے بلکہ یہ کوشش بھی کی جائے کہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں کی ساخت اور سانچہ شریعت اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق تشکیل پاجائے۔
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی تفریح کی گنجائش ہے اور نہ کوئی خوشی منانے کی گنجائش ہے۔ اسلام میں اگر کوئی داخل ہوگیا تو اس کاکام یہ ہے کہ خشک زندگی گزارے اور ہرقسم کی مسرت، خوشی اور سیروتفریح سے بالکل الگ ہوکر ایک تارک الدنیا کے طورپرزندگی بسر کرے۔یہ ایک رائے ہے جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جویہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات اور نماز روزے کانام ہے۔ نماز پڑھ لی تو گویا اللہ پر بڑا احسان کر لیا۔ رمضان کے روزے رکھ لیے تو بہت بڑا احسان ہوگیا۔ اس کے بعد ہم جو جی چاہے کریں۔ ہندوؤں کی نقل کریں، عیسائیوں کی نقل کریں، یہودیوں کی نقل کریں، بدکردار اباحیت پسند لوگوں کی نقل کریں۔ جو جی چاہے کریں کہ ہمیں تفریح اور خوشی کے نام پر دنیا کی ہر چیز کرنے کا اختیار ہے۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں شریعت کے مزاج اور تقاضوں کے خلاف ہیں، شریعت کی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تفریح اور خوشی اور مسرت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیاہے؟
تفریح کا مفہوم
جس کو ہم تفریح کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تفریح کے لغوی معنی ہیں دل کو فرحت بخشنا۔ آپ گرمی کے موسم میں کہیں دور سے آرہے ہوں، سخت تکان اور پیاس ہو اور کسی اچھے شربت کا ایک ٹھنڈا گلاس پی لیں تو دل کو ایک فرحت پہنچتی ہے، خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے فراہم کرنے کو تفریح کہتے ہیں۔ جس طرح جسم کی تفریح ہوتی ہے، عقل کی تفریح بھی ہوتی ہے، ذہن کی تفریح بھی ہوتی ہے، جذبات واحساسات کی تفریح بھی ہوتی ہے، دل کی تفریح بھی ہوتی ہے اور یہ تفریح انسانی مزاج، انسانی طبیعت، انسانی جذبات واحساسات کو regenerate کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انسان ایک ماحول سے اکتا جاتا ہے، بعض اوقات ماحول کی یکسانیت اسے بور کردیتی ہے، وہ پریشان ہوجاتاہے، اس بنا پر ماحول میں جدت پیدا کرنے کے لیے اسے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ضرب المثل ہے: کل جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتاہے، ہرنئی چیز میں ایک لذت ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ نئی چیز میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی پرانی چیز کو بھی نئے انداز سے پیش کیا جائے تو اس میں بھی ایک نیاپن محسوس ہوتاہے۔ آپ گھر میں جائیں اور گھر کے فرنیچر کو ایک نئے انداز سے ترتیب دے دیں، اس کی تشکیل بدل دیں تو کمرہ نیا معلوم ہونے لگے گا۔ پرانی کتابیں نکالیں، انہیں نئی ترتیب دے دیں، ان کی نئی جلدیں بنوالیں تو آپ کو اس میں ایک نیا پن اور اپنائیت محسوس ہونے لگے گی، ایک خوشی محسوس کریں گے۔ آپ لباس کی تراش خراش میں تھوڑی جدت پیدا کر لیں تو آپ کو اچھا لگے گا، خوشی محسوس ہوگی۔
گویا جدت میں انسان لذت محسوس کرتاہے اور نئے پن میں ایک تفریح محسوس ہوتی ہے۔ عام معمول سے ہٹ کر انسان جب کوئی نئی چیز کرتاہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کی وجہ سے تفریح محسوس ہوتی ہے، اس تفریح سے جذبے اور احساس میں ایک نئی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، تفریح کے لیے پہاڑوں پر جاتے ہیں اور جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں، وہ تفریح کے لیے شہروں میں آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں سے لوگ یہاں اسلام آباد آتے ہیں، فیصل مسجد آتے ہیں اور اس گھاس پر بیٹھ کر تفریح محسوس کرتے ہیں۔ جس ماحول میں ہمیں کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، وہ اس ماحول میں پورا دن گزارتے ہیں۔ جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، وہ چھانگا مانگا جاتے ہیں اور چھانگا مانگا کے رہنے والے لاہور میں آتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیاجاسکتا ہے کہ جو آدمی جس ماحول میں رہتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ نیا ماحول تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت نے انسان کے تمام فطری تقاضوں کی تکمیل کا سامان کیا ہے، اس تقاضے کی تکمیل کا سامان اور اس سلسلے میں ہدایات بھی شریعت میں موجود ہیں۔ لیکن اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی حدود کیا ہیں؟ اس پر ابھی بات ہوگی۔ لیکن اس حد تک ہر شخص اتفاق کرے گا کہ لوگ اپنے مزاج اور طبیعت کو ایک جدت سے ہم آہنگ کریں، اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشیں، اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، اپنی کارکردگی میں اگر کمی آرہی ہے، کوئی سستی واقع ہورہی ہے تو اس سستی کو دور کریں، یہ بات شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے، شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔
لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں کہ دوسری اقوام میں تفریح یا تہوار کا تصور کیا ہے؟ تہوار جس کو کہتے ہیں، یہ بھی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھاجاتا ہے۔ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ فلاں تہوار آئے گا تو تفریح کے مواقع ملیں گے۔ اس موقع پر تفریح کریں گے تو ایک نیا پن محسوس ہوگا۔
اقوام عالم میں تفریح کا تصور
مختلف اقوام نے اپنے اپنے لیے جو تہوار اپنائے ہیں، ان میں کچھ چیزیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مشرق کی قومیں ہوں یا مغرب کی، عیسائی ہوں یا یہودی، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہندو ہوں یا سکھ ہویا کوئی اور قوم ہو، ان میں سے اکثر اقوام میں بلکہ اگریہ کہاجائے تو غلط نہ ہوگا کہ سب ہی اقوام میں تہوار کا تصور یہ تھا کہ موسم کی تبدیلی کو نقطہ آغاز قرار دیاجائے۔ انسان تبدیلی سے خوش ہوتا ہے۔ جب تک سردی نہیں آئی ہوتی تو سردی کا منتظر رہتا ہے۔ سردی آجاتی ہے تو گرمی کا انتظار شروع ہوجاتا ہے۔ پھر گرمی آتی ہے تو اس سے پریشان ہوکر سردی کا منتظر رہتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتاہے۔ چونکہ یہ انسان کا عام مزاج ہے، اس لیے مختلف اقوام نے موسم کی تبدیلی کو ایک تہوار قرار دیا۔ قدیم ایرانیوں نے اس مقصد کے لیے نوروز مقرر کیا۔ انہوں نے ایک خاص دن کو موسم بہار کا نقطہ آغاز قرار دیا اور یہ سمجھا کہ اس دن ایک نیاپن ماحول اور کائنات میں پیدا ہواہے، اس لیے اسے ایک خاص انداز سے مناتے ہیں۔ کچھ اور اقوام ہیں جو سردی کی آمد کو مناتی ہیں۔ کچھ اور اقوام ہیں جو کسی خاص موسم کی آمد کو مناتی ہیں۔ کوئی گرمی کی آمد کو مناتا ہے، کوئی ہولی کے نام سے جب گرمی آتی ہے تو ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا غور کریں تو کسی خاص موسم کی آمدورفت سے کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پھر موسم کی آمدورفت ہر علاقے کے لیے مختلف ہوگی۔ فرض کیجیے کہ موسم کی آمد پرجشن منانا اچھی بات ہو یا کم از کم بری بات نہ ہو تو موسم کی تبدیلی ہمارے پاکستان میں فرض کیجیے فروری میں ہوگی۔ لاہور میں فروری ہی میں ہوجاتی ہے، اسلام آباد میں مارچ میں ہوتی ہے۔ شمالی علاقہ جات میں اور آگے جائیں تو اپریل میں ہوتی ہے۔ مزید آگے جائیں تو جون میں ہوتی ہے۔ اور مزید آگے چلے جائیں توپورا سال نہیں ہوتی۔ سال بھر برف باری رہتی ہے۔ ہمارے مغربی علاقوں میں چلے جائیں تو بلوچستان میں شاید جنوری ہی کے کچھ دن سردی رہتی ہو۔ یہ جغرافیائی حالات ہیں جس سے اندازہ کرلیں کہ ہر علاقے اور ہر ملک میں ایک نئے وقت میں موسم کی تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے اگر موسم کی تبدیلی کو اسلام بطور جشن کے یا بطور تہوار کے مانتا تو یہ ایک عالم گیر برادری کے لیے قابل عمل نہ رہتا۔ ایک ایسی عالمی برادری جو دنیا کے ہر ملک اور ہرگوشے میں پائی جاتی ہے، جو امریکہ سے لے کر چین تک اور سائبریا سے لے کر انتہائی جنوبی علاقوں سڈنی اور کیپ ٹاؤن تک میں موجود ہو، وہ کسی ایک دن کو موسم کی تبدیلی کانقطہ آغاز قرار نہیں دے سکتی۔ اس لیے کوئی ایسا تہوار موسم سے وابستہ نہیں ہوسکتا جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہو۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے موسموں کو تہوار کیوں نہیں قرار دیا۔ اس لیے نہیں قرار دیا کہ یہ بات اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، اسی بنا پر قابل عمل نہیں ہے۔
کچھ اور اقوام نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں دیوتاؤں کے پرانے قصے مشہور ہیں کہ فلاں دیوتا سے یا فلاں دیوی سے یا فلاں بت سے وابستہ یہ واقعہ ہے ، وہ قصہ ہے۔ یہ قصے فرضی تھے یا حقیقی، انہوں نے ان کی یاد منانی چاہی اور انہوں نے ان کے نام پر تہوار مقرر کرلیے۔ اکثروبیشتر دیوتاؤں کے تہوار مشرکانہ ہیں ۔ مشرکانہ یادوں، مشرکانہ اعمال اور مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر یہ تہوار مقر ر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اولمپک گیمز کیا ہیں؟ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ فتویٰ کوئی عالم دے گا۔ لیکن یونانیوں میں اولمپک ایک دیوتا تھا جو کھیلوں کا دیوتا کہلاتا ہے، اس کے نام پر یہ اولمپک گیمز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف دیوتاؤں کے ناموں پر تہوار ہوا کرتے تھے۔ یہ اکثر یونانیوں کے یا رومیوں کے تہوار ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی دیویاں وابستہ ہیں، ان کی یادیں وابستہ ہیں، ان کے ناموں سے یہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں برصغیر میں رام کی لیلا ایک تہوار ہوا کرتا تھا۔ میرا بچپن ہندوستان میں گزرا، اس لیے مجھے کچھ چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ غالباً ۱۹۵۶ء کی بات ہے، میں اپنے اعزہ کے ہاں انڈیا گیا ہوا تھا۔ ہماری والدہ کی نانی محترمہ تھیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ کی ولیہ خاتون تھیں۔ کسی ولی خاتون کا تصور جب میرے ذہن میں آتا ہے تو ان کا آتا ہے۔ جب رام کی لیلا نکلنے والی تھی تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بچہ باہر نہ نکلے۔ بچوں کو جس چیز سے منع کریں، اسی کا اشتیاق ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک کمرہ تھا جو اسٹور کے طور پرگندم وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس میں ایک کھڑکی تھی، ہم کئی بچوں نے چارپائیاں اورسیڑھیاں کھڑی کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اماں سے نظر بچا کر اس کھڑکی سے چڑھ کر دیکھیں گے کہ رام کی لیلا کیا ہوتی ہے؟ یوں ہم نے رام لیلا کا جلوس دیکھا۔ اس میں کئی چیزیں دلچسپی کی تھیں جو کسی بھی بچے کی دلچسپی کی ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص جس نے ایک خاص طرح کے سوانگ بھرا ہوا تھا، وہ ہاتھی کے اوپر سوار تھا اور لوگ اس کے پاؤں چوم رہے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے دو تین خواتین جنہوں نے بے تحاشا کا میک اپ کیا ہوا تھا، لباس بھی بے ہودہ سا تھا، وہ اونٹوں، ہاتھیوں اور گھوڑوں پر سوار چلی آرہی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا جلوس تھا جس میں طرح طرح کی خرافات تھیں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہت عرصے بعد یہ پتہ چلا کہ رام لیلا کیاہوتی ہے؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْْنَہُمَا لٰعِبِیْنَ (الانبیاء :۱۶) ہم نے آسمان اور زمین کو کسی کھیل میں پیدا نہیں کیا۔
ممکن ہے یہ سوال آپ کے دل میں بھی آیا ہو کہ کون کہتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل میں پیدا کیا ہے؟ جب میں نے اس آیت کا ترجمہ پہلی بار پڑھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کون سمجھتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ آپ نے یہ سب نعوذ باللہ کھیل میں پیدا کیاہے ۔پھر جب کچھ عرصے بعد ہندو مذہب پر کتابیں پڑھیں تو معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رام پوری کائنات کا خالق اکبر ہے، جس کی یادگار کے طور پر وہ ایودھیا میں مندر بنانا چاہتے ہیں جو اس کی جنم بھومی ہے۔ خدا ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو وہ تنہا تھا۔ وہ اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہوتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے؟ اس کی تفصیل بیان نہیں کی جاسکتی، کیوں کہ نہایت فحش خرافات اور بے ہودہ چیزیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ر ام نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے میل سے ایک لڑکی پیدا کی، دل بہلانے کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ کچھ دن تو دونوں کا دل بہلارہا، پھر یہ بور ہونے لگے تو سوچا کہ کیا کریں؟ پھر انہوں نے کچھ کرنے کے لیے کائنات بنائی۔ تو یہ ساری کائنات انہوں نے دل بہلانے کے لیے بنائی ہے۔ لیلا کائنات کو کہتے ہیں، رام کی لیلا یعنی یہ پوری کائنات رام کی لیلا ہے۔ رام نے اپنے کھیل کود کے لیے، اپنی تفریح کے لیے یہ پوری کائنات یہ سارا سنسار سجایا ہے۔ جب اس کا دل بھرجائے گا تو وہ اسے توڑ دے گا۔ پھر کچھ اور شروع کردے گا، یہ ہے رام لیلا اور قرآن پاک میں اس کی تردید ہے کہ ہم نے کائنات کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔
آپ دیکھیں کہ عرب میں کسی کے حاشیۂ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسلام ہندوستان میں جائے گا، وہاں ایک ایسی فضول قوم ہوگی جو اس طرح کے عقائد رکھتی ہوگی جس کی تردید قرآن پاک میں پہلے دن سے موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو کئی لوگوں سے سنا کہ یہ ایک تہوار ہے، ہندوؤں کی کلچرل چیز ہے۔ آخر مسلمان بھی یہاں رہتے ہیں، انہیں ہندوؤں کے کلچر میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اگریہ معلوم ہو کہ یہ ایک خالص بے ہودہ، مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے تو وہ کبھی ایسا خیال تصور میں بھی نہ لائے۔ اب ایک موحد انسان جو خالق کائنات پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن پاک کے نظریہ توحید کو مانتا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان کا مزاج اور اس کی طبع سلیم برداشت نہیں کرسکتی کہ کسی بھی کلچر کے، کسی ثقافت کے نام سے وہ رام کی لیلا میں شرکت کرے۔ ہندو کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان نہ اس میں شرکت کرے نہ اس پر اعتراض کرے۔ اگر اعتراض نہیں کرسکتے تو کم از کم گھر میں بیٹھیں۔ اکثر وبیشتر تہواروں کایہی حال ہے کہ وہ مختلف اقوام کے، بت پرستوں کے تہوار ہیں یا خاص واقعات جو قوموں کی تاریخ میں ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر واقعات کا تعلق ان کے کافرانہ عقائد اور بت پرستانہ تصورات سے ہے، ان کی یاد میں یہ تہوار منائے جاتے ہیں۔
یہ بات کہ ہندوؤں میں مختلف چیزوں کے دیوتا ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ ہندو ہر اس چیز کو جو کسی طرح کا نفع یا ضرر رکھتی ہو، دیوتا مانتے ہیں۔ ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر فطری مظہر کا بھی ایک دیوتا قرار دیاہے۔ ایک دولت کا دیوتا ہے، ایک غریبی کا دیوتا ہے، ایک بیماری کا دیوتا ہے۔ اگنی دیوی کا نام آپ نے سنا ہوگا جو دولت کی دیوی ہے۔ جب کہیں اترتی ہے تو وہ اندھی ہے، اس کی نگاہ کمزور ہے، اسے نظرنہیں آتا۔ جہاں زیادہ روشنی ہو، وہاں اتر جاتی ہے۔ جب اترنے کا وقت ہوتا ہے تو گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ شب برات کے چراغاں کایہ پس منظر ہے۔ جب وہ اترتی ہے تو زیادہ چراغاں ہوتاہے تاکہ جہاں زیادہ روشنی ہوگی، وہ وہاں اترجائے گی، کیونکہ وہ ندھی ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ جب وہ اترے گی تو دولت آجائے گی۔ اب غور کرلیجیے کہ یہ عقیدہ معلوم ہو تو شب برأت کے پٹاخوں کی خرافات میں کون مسلمان شرکت کر سکتا ہے؟ شب برات میں چراغاں کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔
اسی طرح ان کے ہاں موسم بہار کی بھی ایک دیوی ہے۔ یہ دیوی زرد کپڑے پہن کر اترتی ہے اور ایسی جگہ اترتی ہے جہاں زیادہ زردی ہو۔ اس گھر میں زیادہ بہار آجاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں میں اور ہندو زدہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں ایک خاص دن ہی زردکپڑے پہننے کا بڑا رواج ہے۔ گیندے کے زرد پھول، زرد کپڑے، زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے۔ لوگ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز پراعتراض ہے، زعفران پر کیا اعتراض ہے؟ مجھے زعفران پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ زعفران ضرور کھائیں، استعمال کریں۔ جو مرضی کریں، لیکن اگر ایک خاص دن میں آپ زعفران اس لیے استعمال کریں کہ اس کا رنگ پیلا ہے اور پیلے رنگ میں حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس موسم بہار کی دیوی کو پیلا رنگ پسند ہے اور وہ اس روز اترتی ہے اور پیلا رنگ جہاں ہوتا ہے، وہاں وہ زیادہ اترتی ہے تو پھر مجھے تامل ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے عقیدے کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔
جو مسلمان خداے و احد کو مانتا ہو اور ہر چیز اللہ کے حکم سے مانتا ہو، وہ کسی دیوی کے چڑھنے اترنے کا ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بظاہر چیزیں ثقافتی اور کلچرل معلوم ہوتی ہیں اور کچھ لوگ سادہ لوحی میں یا زبردستی، دھونس اور دھاندلی میں اس کا کلچرل، ثقافتی یا معاشرتی پہلو سامنے رکھتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد پر لوگ خوشی منالیں اور پتنگ اڑالیں تو آ پ کاکیا نقصان ہے؟ پتنگ اڑانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اڑانا چاہتا ہے تو اڑائے، لیکن پوری قوم کوپتنگ بازی پر لگا دیں اور پوری قوم کی ساری توجہ اس جانب لگ جائے، درجنوں آدمی اس روز مارے جائیں۔ ایک طرف انسانی جان کی قدر وقیمت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ایک جانب ڈگنٹی آف مین (Dignity of man) کی بات کی جاتی ہے۔ اگر کہیں اسلام کے حوالے سے کہا جائے کہ فلاں آدمی نے میری انگلی کاٹ دی، لہٰذا قصاص میں اس کی انگلی کاٹ دی جائے تو وہاں تو ڈگنٹی آف مین (Dignity of man) یادآجاتی ہے کہ اس قاتل، ڈاکویا چور کی، جس نے حملہ کر کے میری انگلی توڑ دی تھی، اس کی انگلی سلامت رہے، میری انگلی کی خیرہے، لیکن جہاں درجنوں آدمی روزانہ موت کے گھاٹ اترتے ہوں، اس کا کسی کو احساس نہ ہو، یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔
تو یہ تہوار کی ایک دوسری قسم ہے۔
تہوار کی ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے اور مختلف اقوام میں یہ قسم بھی پائی جاتی ہے کہ کسی خاص حکمراں کو اس دن حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، کسی خاص خاندان کو تخت نشین ہونے کا موقع ملا، کوئی خاص بادشاہ مرگیا، کوئی دوسرا بادشاہ تخت پربیٹھ گیا تو اس دن سے تہوار شروع ہو گیا، اس روز کو یادگار کے طور پر منایاجانے لگا۔ یہ دنیا کی ہر قوم میں ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے تہوار بدلتے بھی رہتے ہیں۔ جس بادشاہ کا عروج ہوتاہے، اس کی تخت نشینی تہوار بن جاتی ہے۔ جب اس کا زوال شروع ہوجاتا ہے تو اس کے تہوار کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس طرح کے تہوار ماضی میں ہزاروں آئے اور ہزاروں ختم ہوگئے جن کے بارے میں آج کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تہوار کافی دن چلتا ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے برادر ملک مصر میں فرعون کا بڑا رواج تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرعون ان کی تاریخ کابڑا فرماں روا گزراہے، لہٰذا وہ ان کے لیے ایک ہیرو اور رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں یہ بحث چلی، باقاعدہ تحقیقیں ہوئیں، جامعات میں مقالے لکھے گئے کہ ان میں سے سب سے بڑا فرعون کون تھا جس کی یاد منائی جائے؟ فرعون تو لقب تھا، ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، لیکن ان میں سے متعین فرعون جو ان میں سب سے بڑا ہوا، اس کی نشان دہی کی جائے۔ پتہ چلا کہ وہ وہی تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا،چنانچہ اس کو ہیرو بنانے کی کوشش شروع ہوئی۔ اب ہیرو تو بنالیا، اس کے نام کے بت بھی بنائے گئے، ہوٹل بنائے گئے، لیکن اس میں بڑی تحقیق کرنی پڑی کہ وہ پیدا کس تاریخ کو ہوا اور مرا کس تاریخ کو تھا، تاکہ اس تاریخ کو جشن منایا جائے، لیکن نہ اس کی پیدائش کی تاریخ کا پتہ چلا نہ مرنے کا، اس لیے جشن والی بات تو ختم ہوگئی۔
یہ بھی ایک انتہا ہے۔ جب کسی فرد کو رول ماڈل بنایاجائے اور اس کی ذات کو مرکز بنایاجائے تو یہ نتائج نکلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو کسی تہوار کا موضوع قرار نہیں دیا۔ نہ آپ کے یوم پیدائش کوصحابہ نے تہوار بنایا، نہ اسے ہجری کیلنڈر کاآغاز قرار دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کیلنڈر شروع ہوا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ذاتی فعل وعمل سے ہوا۔ آپ کی شادی بھی ہوئی، آپ کی اولاد بھی ہوئی، بہت سے واقعات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے بالاتفاق ان میں سے کسی واقعے کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار نہیں دیا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے کسی واقعے کو تہوار قرار نہیں دیا۔
کچھ اور اقوام میں تہواروں کا ایک اور سبب پایاجاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی خاص جنگ میں کسی کو کامیابی ہوئی تو اس کی یاد میں تہوار منایاجانے لگا۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی کامیابیاں دیں۔ غزوۂ بدر میں بڑی کامیابی ہوئی جسے قرآن نے یوم الفرقان قرار دیاہے۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیاہے، فتح مکہ جیسی کامیابی ہوئی،لیکن ان میں سے کسی بھی جنگ میں کامیابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کاتہوار یا یادگار قرار نہیں دیا۔ صحابہ کرامؓ نے ان میں سے کسی کی یاد نہیں منائی۔ آپ نے سیرت، تاریخ یا صحابہ کرام کی سوانح عمری میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے یوم بدر منایا ہو، انہوں نے فتح مکہ کا دن منایا ہو، انہوں نے صلح حدیبیہ کی کامیابی کا جشن منایا ہو۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج تفریح اور تہوار کے بارے میں کیا ہے؟
اسلام کا تصور تفریح
اسی طرح سے آپ غور کریں کہ جتنے تہوار ہیں جن مواقع پر انسان تفریح مناتے ہیں، ان میں سے کسی موقع کو اللہ تعالیٰ نے تفریح کے لیے یا تہوار کے طور پراختیار نہیں کیا۔ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: لکل قوم عید وھذا عیدنا۔ ہرقوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عیدیں یہ دو ہیں یعنی عیدالفطر اور عیدالاضحی۔ آپ دیکھیں کہ نہ کسی بادشاہ کی تخت نشینی سے ان کا تعلق ہے، نہ کسی جنگ میں کامیابی سے تعلق ہے، نہ کسی ریاست وسلطنت کے قیام سے تعلق ہے، نہ کسی خاندان کی حکمرانی سے تعلق ہے کہ فلاں خانوادۂ شاہی کا عہدشروع ہوگیا، نہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش ووفات سے تعلق ہے۔ ان دونوں عیدوں کا تعلق دو خالص اصولوں سے ہے، دو ایسے اصول جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا ہمیشہ ممتاز ترین وصف رہے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الٰہی کانزول، قرآن مجید کی عطا جس کے شکر میں عید الفطر منائی جاتی ہے اور دوسرے اللہ کے حضور اتنی بڑی قربانی کہ اس سے بڑی قربانی کسی انسان نے کبھی نہیں دی، اس کی یاد میں عید الاضحی منائی جاتی ہے۔ ایک کاز کے لیے، اللہ کے حکم کے لییاپنی عزیز ترین چیز کی قربانی دینے کی جو مثال قائم ہوئی، عید الاضحی اس کی یادگار ہے۔ گویا تفریح کا تعلق بھی اور تہوار کا تعلق بھی نظریے ا ور اصول کے ساتھ ہے۔
نظریہ، اصول اور تفریح، یہ آپس میں اس طرح سے باہم مربوط ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر اس میں آپ کو کوئی خاص معنویت معلوم نہیں ہوگی۔ آدمی سوچ سکتا ہے چلیے مسلمان بڑے مذہبی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کسی حکومت کے قیام پر نہیں، قرآن کے نزول پرجشن منایا، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ لیکن درحقیقت اس میں بڑی خاص بات پوشیدہ ہے۔ تفریح کرنے کے مواقع ہم نے دیکھ لیے کہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو قومی مواقع ہوئے۔ اس کے بعد انفرادی مواقع ہوتے ہیں کہ فرد کو خوشی ہوتی ہے۔ کسی کی شادی ہے، اس کو خوشی ہوئی۔ کسی کو اللہ نے بیٹا دیا، خوشی ہوئی۔ کسی کو کامیابی ہوئی، اچھی ملازمت مل گئی، کاروبار میں ترقی ہوگئی، اس طرح کے ذاتی مواقع بہت آتے رہتے ہیں اور ہر ذاتی موقع پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تلقین فرمائی بلکہ خود بھی اس پر عمل کرکے دکھایا۔ گویا مواقع دو طرح کے ہوئے: قومی، ملی اور اجتماعی مواقع جو شریعت نے دو رکھے ہیں، یعنی عید الفطر اور عیدالاضحی جن کا تعلق دو بڑے اصولوں سے ہے۔ اس کے بعد انفرادی مواقع جو ہر فرد کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور مشہورہیں۔ شادی بیاہ ہے، پیدائش ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، مکان نیا بنایا ہے، اس طرح کے اور کئی معاملات ہوسکتے ہیں۔ کچھ اور مواقع بھی ہوسکتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو کسی بات پر خوشی ہوئی، مثلاً قیام پاکستان ہے، یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ مصر کے مسلمان ہیں، انہیں ۱۹۷۳ء میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل پر فتح دی۔ ۶؍ اکتوبر کو وہ جشن مناتے ہیں۔ ایک بڑے دشمن پر اللہ نے انہیں کامیابی دی، اس پر وہ خوشی کااظہار کرتے ہیں۔ یہ عارضی یاعلاقائی قسم کے مواقع ہوسکتے ہیں، شریعت ان سے نہیں روکتی۔
اسلام نے تفریح کے جو مواقع بتائے ہیں، ان میں ذاتی مواقع، ملی اور قومی سطح کے مواقع اور علاقائی سطح پر ہرخوشی اور جائز کامیابی کے مواقع شامل ہیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہوں۔ ان کی خوشی منانے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا اہتمام نہ صرف جائز ہے، بلکہ قرآن مجید کے بالواسطہ اشارے کے مطابق مسنون اور بہترہے: قُلْ بِفَضْلِ اللّٰہِ وَبِرَحْمَتِہِ فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُوا (یونس: ۵۸) اللہ کے فضل کو یاد کرکے خوشی کا اظہارکرو، فرحت کا اظہار کرو۔ یہی تفریح ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَۃِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (الضحیٰ: ۱۱) اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرے، اسے بیان کرو۔ کیونکہ جب نعمت کو بیان کروگے تو نعمت کی قدر ہوگی، ورنہ بھول جاؤ گے کہ اللہ نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے۔ اگر اللہ کی نعمت کااظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرو گے تو یاد نہیں رہے گا کہ اللہ نے بڑی نعمت دی تھی۔
تفریح اور تہوار جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک فطری ضرورت ہے اور ہر انسان کسی خاص موقع پر خوشی منانا چاہتا ہے، لیکن اگر خوشی اور تفریح حدود سے نکل جائے گی تو اس سے اخلاقی، معاشی، معاشرتی بہت سی قباحتیں پیدا ہوں گی۔ ایک قباحت کا ابھی ذکر ہوا۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر چند سال پہلے۲۲ افراد ہلاک ہوئے اور چالیس پچاس کروڑ روپے ضائع ہوئے۔ اس طرح کا کوئی تہوار اسلام نے نہیں رکھا۔ اسلام نے تہوار اور تفریح کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ ایک تہوار تو وہ ہے جو ایک متعین دن منایاجائے اور ساری امت اور ساری قوم مل کر اس میں شریک ہو اور اپنی خوشی ومسرت کااظہار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکل قوم عید وھذا عیدنا (صحیح بخاری) ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری عید یہ ہے جو ہم منا رہے ہیں۔
تفریح کی حدود
لیکن ان دو تہواروں کے علاوہ ویسے بھی انسان کا کبھی کبھی یہ جی چاہتا ہے کہ اپنے عام معمولات اور ماحول سے نکل کر کسی نئے ماحول میں جائے، کسی نئی کیفیت کو محسوس کرے اور چوں کہ جدت کے احساس میں لذت ہے، اس لذت سے اپنی قوتوں،حوصلوں، اپنے مزاج کو تازہ کرے، دماغ کو تازہ ہوا دے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ یہ بات اگر حدود کے اندر نہ ہو تو عملاً ممکن نہیں ہے۔ انسانوں کی ہرسرگرمی کے لیے حدود درکار ہیں۔ یہ ایسی واضح اور بدیہی بات ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہر مسلم، غیر مسلم اس کو تسلیم کرے گا کہ ہر انسان کی خواہش کی تکمیل کو حدود کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حدود کی پابندی ضروری نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ ہر خواہش کی تکمیل حدود کا تقاضا کرتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے مزیدار سے مزیدار کھانے ملیں، لیکن اس کی حدود ہونی چاہییں۔ اگر اس کی حدود نہ ہوں تو میں آپ کے گھر میں گھس جایا کروں اور جو اچھا کھانا ملا کرے، کھاجایا کروں۔ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ہرشخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہو۔ اگر کوئی حدود کا پابند نہ ہو تو ہم میں سے ہر شخص باہرنکلے اور جو اچھی گاڑی نظر آئے، اسے ڈرائیو کرکے چلتا بنے۔ ظاہر ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے حدود ہونی چاہئیں، اخلاقی حدود ہونی چاہئیں۔ ہرنوجوان شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے، اچھی خاتون کے ساتھ گزرے۔ اس خواہش کو حدود کا پابند نہ بنایا جائے تو معاشرہ جنگل بن جائے گا۔ ہرنوجوان خاتون کی خواہش ہے کہ اس کے گھر کا اچھا ماحول ہو، اس کااپنا گھر ہو، اس کا شوہر ہو، اس کے بچے ہوں، لیکن اگر اس کو اخلاقی حدود کا پابند نہیں بنایا گیا تو معاشرہ بداخلاقی کے سیلاب میں بہہ جائے گا۔ اس لیے یہ بات کہ انسان کی خواہشات بلکہ جائز خواہشات کو بھی حدود کا پابند ہوناچاہیے، یہ دنیا کا ہر سلیم الطبع انسان تسلیم کرے گا۔ کوئی سلیم الطبع انسان اس سے اختلاف نہیں کرسکتا۔ اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ سلیم الطبع انسان نہیں ہے۔ اس سے بات کرنا بے کار ہے۔
جب یہ بات مان لی گئی کہ ہر انسان اپنی خواہشات کو حدود میں رہ کر ہی پورا کرنے کا پابند اور مکلف ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حدود کیا ہیں اور ان حدود کو کون مقرر کرے گا؟ میں مقرر کروں گا یا آپ؟ اگر میں آپ کے لیے مقرر کروں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کے لیے یہ حدود مقرر کرنے والا؟ مجھے آپ پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ میں آپ کے لیے اس قسم کی حدود مقرر کروں؟ اور اگر آپ مقررکریں تو یہی سوال میں کر سکتا ہوں کہ آپ کویہ حدود مقرر کرنے کاکیا اختیار حاصل ہے؟ آپ کو کیا برتری حاصل ہے اور میں آپ کی مقرر کردہ حدود کا پابند کیوں ہوں؟ یا کوئی اور ہمارے لیے کرے تو کیوں کرے؟ اس لیے کہ جو شخص بھی یہ حدود مقرر کرے گا، اس کے اپنے خیالات ہوں گے، وہ اپنی تحدیدات سے محدود ہوگا، اس کا تجربہ محدود ہوگا، اس کا اپنا مخصوص پس منظر ہوگا، وہ کوئی بسنت کا رسیا ہوا تو بسنت کے بڑے احکام وضع کردے گا اور کوئی رام لیلا کا رسیا ہوا تو اس کو منانے کی گنجائش پیدا کرے گا اور بہت خشک آدمی ہوا تو جائز تفریح کے راستے بھی بند کردے گا، اس لیے کسی انسان کو یہ حدود مقرر کرنے کا فریضہ سونپنا بڑا خطرناک ہے۔ اگر وہ اچھی حدود بھی مقرر کردے تو وہ حدود چند مہینے، چند سال، چندعشرے چلیں گی، اس کے بعد وہ از خود حالات سے غیر متعلق ہوجائیں گی، بے کار ہوجائیں گی۔ جب وہ حالات بدل جائیں گے، زمانہ تبدیل ہوا تو وہ حدود بھی بدلنی پڑیں گی۔ پھر کیاہوگا؟ اس لیے بہتر ہے بلکہ ضروری ہے کہ یہ حدود کوئی ایسی قوت مقرر کرے جو موجودہ تحدیدات سے محدود نہ ہو، جو موجودہ قیود سے مقید نہ ہو، جو زمان ومکان سے ماورا ہو، جو کسی کے مفاد سے متاثر نہ ہو، جس کے پیش نظر کسی خاص گروہ یا فرد کی مصلحت نہ ہو، جو سب کو یکساں نظر سے دیکھتی ہو، جس کی نظر میں کالا اور گوراسب برابر ہوں، جس کی نظر میں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ ہو۔ وہ صرف خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی حدود جو سارے انسانوں کے لیے ہوں اور سارے انسان اس پر یکساں طور پرعمل کرسکتے ہوں، وہ حدود خالق کائنات ہی مقرر کر سکتا ہے۔
وحئ حق بنندہ سود ہمہ
در نگاہش سو دوبہبود ہمہ
صرف وحی حق ہے جو ہر شخص کے مفاد کودیکھتی ہے۔ اس کی نگاہ میں ہر انسان کا فائدہ، کامیابی اور فلاح ہے۔ وہ ذات متعین کرے گی کہ کیا حدود ہیں! وحی حق نے کیا حدود مقرر کی ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی حد ایسی نہیں ہے جس سے کوئی سلیم الطبع انسان بھی اختلاف کرسکے۔ کوئی انسان جس میں اخلاق کی رمق ہو، جس میں فطرت سلیمہ ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مشرقی ہو یا جنوبی، عالم ہو یاجاہل، اسلام کا حوالہ دیے بغیر اس سے پوچھیں تو وہ اس کو تسلیم کرے گا۔
سب سے پہلی حد جو کسی تفریح کو منانے کے لیے درکار ہے، جس کی حدسے آگے نہیں جانا چاہیے، وہ ہے حیا۔ انسان کو حیا کا پابند ہونا چاہیے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دریا کی سیر کو جاؤں۔ اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ وہاں خواتین بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کپڑے اتار کر دریا میں دوڑ لگانا شروع کر دے تو اسے کوئی پسند کرے گا؟ مشرق ومغرب کا کوئی سلیم الطبع انسان اس کو پسند نہیں کرے گا۔ دس مردوں کا کہیں اجتماع ہو، چار خواتین جا کر تیراکی کا لباس پہن کر وہاں تیرنا شروع کر دیں تویہ اسلام کے تصور حیا کے خلاف ہے۔ حیا اور اخلاق بنیادی حد ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے اور حیا کے آداب کی پاس داری کسی نہ کسی حد تک ہر انسان کرتا ہے۔ یہ توہوسکتا ہے کہ میں حیا کی حد کچھ اور مقرر کروں، دوسرا حد اور مقرر کرے۔ اس پر تو بات ہوسکتی ہے کہ حیا کی حد کہاں مقرر کی جائے، لیکن حیا کی حد مقرر کرنے پر ہرانسان کا اتفاق ہے۔
کافی عرصہ پہلے مجھے کسی مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا، پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پہلی مرتبہ مجھے یہ پتہ چلا اور مجھے کئی رات تک نیند نہیں آئی، عجیب ذہنی کیفیت رہی۔ مجھے پتہ یہ چلا کہ مغربی ممالک میں برہنہ لوگوں کے کلب ہوتے ہیں۔ وہاں جو جاتا ہے، وہ مادر زاد برہنہ رہتا ہے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے۔ اس کے قواعدوضوابط ہیں۔ ایک رسالہ تھا، اس میں کسی کلب کے متعلق قواعد وضوابط لکھے ہوئے تھے۔ ان قواعد وضوابط کی مثال میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ ان بے حیا اور بداخلاق لوگوں میں بھی حیا کا تھوڑا سا تصور موجود تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ جو ہمارے کلب کا ممبر بنے گا، وہ کلب کی چار دیواری سے باہر برہنہ حالت میں نہیں جائے گا۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بداخلاق سے بداخلاق اور بے حیا سے بے حیا انسان میں بھی حیا واخلاق کی کوئی نہ کوئی رمق موجود ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فطری چیز ہے۔ اگر شریعت نے حیا کی شرط رکھی ہے تو وہ انسانی فطرت کے مطابق رکھی ہے۔ کوئی چیز خلاف فطرت یا انسانی مزاج وطبیعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حد ہے۔
دوسری بنیادی حد یہ ہے کہ تفریح یا خوشی منانے میں اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خوشی منائیں، اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، آپ پہنیں۔ اچھا کھانے کو دیا ہے، اچھا کھانا بھی کھائیں۔ دوستوں، رشتے داروں، عزیزوں کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کر گھر میں تقاریب بھی منعقد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے ان چیزوں سے بالکل نہیں روکا، لیکن اسراف وتبذیر سے کام نہ لیں۔ اسراف وتبذیر قرآنی اصطلاحات ہیں۔ اسراف سے مراد کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے اور تبذیر سے مراد ناجائز کام میں خرچ کرنا ہے، خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ ناجائز کام میں ایک پیسہ بھی خرچ کرناتبذیر ہے اور جائز کام میں اگر ایک لاکھ کی ضرورت ہے تو ایک لاکھ خرچ کرنا بھی اسراف نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ایک لاکھ ایک روپیہ خرچ کرنا اسراف ہوگا۔ اگر ایک لاکھ میں کام ہوتا ہے تو ایک لاکھ خرچ کریں، شریعت اس سے نہیں روکتی، لیکن اس سے اوپر اگر دس روپے بھی ہوں گے تو وہ اسراف ہوجائے گا اور اس کا ہر شخص اپنے طور پر فیصلہ کرے گا۔ اس میں کوئی شخص باہر سے آپ کو نہیں بتاسکتاکہ آپ کے لیے اسراف کیاہے۔ تبذیرکی نشان دہی ہوسکتی ہے۔ اگرکام حرام ہے تو اس میں ایک پیسہ خرچ کرنا بھی تبذیر ہے۔ یہ آپ کو شریعت کاعالم بتا سکتا ہے کہ یہ تبذیر ہے یانہیں۔ اسراف کیا ہے؟یہ ہر شخص کے حالات پر منحصر ہے۔ میرے لیے اسراف کچھ اور ہوگا اور آپ کے لیے کچھ اور ہوگا،کسی اور کے لیے کچھ اور ہوگا۔ اپنے حالات کے حساب سے اسراف ہوگا۔
ظاہر ہے اس سے بھی کوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ اللہ نے جو وسائل دیے ہیں، جو مال ودولت دیا ہے، اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ ہمارے مال ودولت کا بھی مالک ہے۔ میری جیب میں جو پیسے ہیں اور آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں، اس کا بھی مالک ہے۔ آپ اس رقم کے امین ہیں۔ آپ اس رقم کے ٹرسٹی ہیں اور رقم کو استعمال کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ میں اس کی مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں۔ یونیورسٹی نے مجھے استعمال کے لیے ایک گاڑی دے رکھی ہے۔ میں بہ طور صدر جامعہ اس گاڑی کو استعمال کرتا ہوں۔ عرف عام میں وہ میری گاڑی کہلاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غازی صاحب کی گاڑی آگئی، غازی صاحب کی گاڑی چلی گئی، غازی کی گاڑی کی مرمت ہوئی۔ حالانکہ یہ میری گاڑی نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، لیکن عام بول چال میں میری گاڑی سمجھی جاتی ہے۔ مجھے ہی اسے استعمال کرنے کا حق ہے، کسی اور کو استعمال کرنے کا حق نہیں۔ تقریباً یہی کیفیت اس مال ودولت کا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ گھر، جائیداد، ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے استعمال کی اسی طرح اجازت دی ہے، جیسے یونیورسٹی نے مجھے گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر میں یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق استعمال کروں گا تو وہ جائز ہوگا، قواعد وضوابط سے ہٹ کر استعمال کروں گا تو وہ ناجائز استعمال ہوگا۔ یونیورسٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کو ذاتی اور سرکاری دونوں ضروریات کے لیے استعمال کرسکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ کروں کہ روزانہ شام کو گھر آکے ایک ڈرائیور کو بلایا کروں کہ میاں اس کو لے جاؤ، کرایے پر چلاؤ اور جو رقم ملا کرے، آدھی تمہاری آدھی میری تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مال ودولت دیا ہے، وہ جائز استعمال کے لیے دیاہے، ناجائز استعمال کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کہے کہ میری دی ہوئی دولت کو کہاں استعمال کرو اور کہاں استعمال نہ کرو۔ یہ حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔
لیکن اگر کچھ لوگ شریعت کے اصولوں سے دلچسپی نہ بھی رکھتے ہوں تو بھی وہ یہ بات تو تسلیم کریں گے کہ مال ودولت انسانوں کی دوسری اعلیٰ وبرتر ضروریات کے لیے ہے۔ تفریح کے علاوہ بھی دوسری اہم ضروریات ہیں، مال ودولت کی زیادہ ضرورت ان کے لیے ہے۔ خدا نخواستہ آپ کے گھرمیں کوئی شدید بیمار ہے، پیسے آپ کے پاس تھوڑے ہیں۔ اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا علاج کروائیں، اور چھ ہزار کا Life saving انجکشن خریدلیں اور یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ چھ ہزار روپے خرچ کر کے آپ چھانگا مانگا چلے جائیں۔ لیکن کوئی معقول آدمی نہیں کہے گاکہ آپ اپنی ضعیف والدہ کا علاج تو چھوڑ دیں اور یہ چھ ہزار روپے جو آپ کے پاس ہیں، ان سے چھانگا مانگا کی تفریح کرنے چلے جائیں۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ اس سے علاج کرانا چاہیے۔ کسی کی تعلیم کاخرچہ ہے، وہ پورا کرنا چاہیے۔ مکان کی چھت گرگئی ہے، بارش سے پانی بہہ رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی، چھ ہزار روپے سے چھت کی مرمت کی ضرورت نہیں، تفریح کرنے جاتے ہیں۔ ہرمعقول اور سلیم الطبع آدمی یہ کہے گا کہ یہ پیسہ تفریح کے بجائے فلاں بنیادی کام میں خرچ ہونا چاہیے۔ گویا جو بات شریعت نے کہی ہے، وہ ہر سلیم الطبع شخص مانتا ہے کہ تفریح کی ضرورت وہاں ہے جہاں باقی ضروریات آپ کی پوری ہوں، جہاں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوگئی ہوں اور اللہ نے جائز وسائل دیے ہوں جو آپ تفریح میں خرچ کرسکتے ہوں، ورنہ جائز ضروریات کو نظر انداز کر کے، اپنے فوری مسائل کو قربان کرکے تفریح کرنا کوئی معقول انسان پسند نہیں کرتا۔ نامعقولوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ جائز خوشی اور مسرت کے جو بھی جائز مواقع ووسائل موجود ہیں بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے، بغیر اخلاقی، انسانی اور شرعی حدود کو توڑے جو بھی طریقہ ہو، اس کواختیار کرسکتے ہیں، چنانچہ بتایا گیا کہ بہترین کپڑے جو انسان کے پاس موجود ہوں، ان کوپہنے، تحفے اور ہدیے کا تبادلہ کرے۔ دوست احباب کو گھر بلانا، تحائف کا تبادلہ کرنا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے: تھادوا تحابوا۔ (طبرانی،المعجم الاوسط، بیروت، دارلکتب العلمیہ ۱۹۹۹ء، ج ۵، ص ۲۵۴، رقم الحدیث ۷۲۴۰) آپس میں تحفہ دو تو محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کو گھروں میں بلاؤ، ایک دوسرے کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو، چاہے کوئی معمولی چیز ہو۔ ضروری نہیں کہ کوئی قیمتی چیز ہی ہدیہ میں پیش کی جائے تو محبت بڑھتی ہے اور معمولی ہو تو نہیں بڑھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: لاتحقرن جارۃ لجارتھا ولو بفرسن شاۃ (صحیح مسلم ،کتاب الزکوٰۃ، باب الحث علی الصدقۃ ولو بالقلیل، رقم ۲۳۷۶)۔ یہاں نون تاکید ثقیلہ ہے جس میں زیادہ تاکید ہے۔ اس کا ترجمہ انگریزی یا اردومیں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسے الفاظ اردو یا انگریزی میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے ہدیے کوحقیر نہ جانے۔ اگر ایک بکری کا کھر بھی تحفے میں آئے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ہدیہ سمجھنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر قدر جذبے کی ہے تو جذبے میں قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ قیمت اس گلاس کی پچاس روپے ہے یا وہ دوروپے کا مٹی کا پیالہ ہے، اگر کسی نے محبت سے پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا ہے تو اصل قدر اس محبت اور جذبے کی ہے اور اس احساس کی ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوا کہ آپ کو وہ چیز پیش کرے، آپ کے ساتھ شیئر (Share) کرے۔ وہ ایک لاکھ روپے کی ہو، ایک روپے کی ہو، ایک پیسے کی ہو، دو پیسے کی ہو۔ اس لیے انسان کے جو بھی وسائل ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہدیے کا تبادلہ کرنا تفریح کا ایک حصہ ہے اور خوشی ومسرت کے اظہار کا اسلامی اور دینی طریقہ ہے۔
بعض مواقع ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ خاندانی میں یہ تفریح کا موقع ہوتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گھر میں جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اظہار کی تلقین فرمائی، وہاں اس میں ایک بڑے رجحان کو آپ نے روکا۔ بڑا رجحان ہوتا ہے اور یہ نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ جی، ایک ہی بیٹا ہے، اس کے ارمان نکالنے ہیں۔ ارمان بھی نکالنے ہیں اور ہر چیز کا جنازہ بھی نکالنا ہے۔ سب اکھڑ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے کہ جی، ایک بچہ ہے، اس کے ارمان نکالنے ہیں۔ خاص طور پر بوڑھے لوگوں کایہ خیال، نانی دادی ہوں کہ جی ہمارا ایک ہی پوتاتو ہے، اس کے بعد کیا ہے۔ اس میں جو بھی راز ہے، سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طرز عمل سے اپنے صحابہ کی تربیت سے ایسی مثال پیش کی کہ آج ہمارے قریب ترین لوگوں میں بھی کوئی کرے تو شاید لوگ ناراض ہو جائیں۔
صحابہ کرامؓ میں سے اول درجہ کس کا ہے؟ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ دس وہ صحابہ کرام جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی اور ان صحابہ کا جن کو حضرت عمرفاروقؓ نے اپنی جانشینی کے لیے نامزد کیا کہ یہ چھ آدمی میرے جانشین ہو سکتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جو ہجرت حبشہ کے موقع پر چند سرداروں میں سے بنا کربھیجے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ ہجرت کرکے مدینہ آگئے۔ آپ اس زمانے کا تھوڑا تصور ذہن میں لائیں۔ تیرہ سال اپنے گھر میں اپنے وطن میں Persecute ہو رہے ہیں اور پریشان کیا جارہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ پھر خدا خدا کر کے ایک ٹھکانہ مل جاتا ہے، سب گھر بار چھوڑتے ہیں۔ کسی نے کاروبار چھوڑا، کسی نے جائیداد چھوڑی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ مکہ کے لکھ پتی آدمی تھے، صف اول کے پیسے والوں میں تھے۔ سب کاروبار چھوڑ کر تن تنہا مدینہ چلے آئے۔ وہاں جاکر ایک انصاری کے گھر میں بیٹھ گئے۔ انصاری نے کہا کہ میری زمین ہے، آدھی لے لو، کچھ یہ کرو، وہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ دو چار دن بازار میں پھرے، کاروبار کیا۔ اللہ نے صلاحیت دی تھی، کاروبار شروع کر دیا۔
عبدالرحمن بن عوفؓ چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ ایک دن آئے تو ذرا نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوشبو لگی ہوئی تھی اور مہندی کا نشان شاید ہاتھ یا پاؤں میں یا جہاں بھی ہوگا، دکھائی دے رہا تھا۔ اثر صفرۃ (زردی کا نشان) کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے عبدالرحمن؟ انھوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ، میں نے شادی کرلی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف بلایا نہیں بلکہ بتایا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہ اچھااتنی طوطا چشمی، اتنی بے وفائی کہ یہاں آکر میں نے سارا ٹھکانا دیا، میں لے کر آیا، میں نے لوگوں کے یہاں ٹھہرایا، مواخات کرائی، میرے کہنے پر لوگوں نے کاروبار میں شریک کیا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ آج اگر یہ ہو توری ایکشن ہوگا کہ اچھا جی، کاروبار میں اتنے مگن ہوئے کہ ہمیں بھول ہی گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ نہ انہوں نے محسوس کیا کہ بلانا ضروری ہے، نہ حضور نے سمجھا۔ آپ نے فرمایا: اولم ولو بشاۃ (ابوداؤدج ۱، ص ۳۲۳، رقم ۲۱۰۹) ولیمہ ضرورکرنا، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ خوشی کا حکم دیا کہ اس کو Celebrate کرو، خوشی مناؤ، چاہے ایک بکری ذبح کرلو۔
اس واقعے پر جتنا غور کریں، اسلام میں شریعت کی ساری حدود سامنے آتی ہیں۔ اعتدال اور توازن کہ جتنے وسائل ہیں، ان کے اندر رہو، غیر ضروری طور پر اس کو مت پھیلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ایک بکری ذبح کرلو اور اس ایک بکری میں جتنے لوگوں کو شریک کرسکتے ہو، کرو۔ ولیمے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ دعوت کرو، لوگوں کو بلاؤ۔ اس میں بعض اوقات لوگوں کے وسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے۔ اگر اس موقع پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ عبدالرحمن! مجھے بھول گئے، مجھے نہیں بلایا تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ ہوتی، اس لیے کہ اس سے یہ سمجھا جاتا کہ اپنے دینی قائد کو اپنی تقریب میں بلاؤ، یہ بلانا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اب کون مسلمان ایسا ہوتا مدینہ میں، مکے میں، اس کے قرب وجوار میں جس کے ہاں شادی ہوتی، تقریب ہوتی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاتا؟ ہر ایک بلاتا۔ کسی کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے جتنے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے پاس تھے، کسی کے ہاں پانی پلانے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی نہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ بغیر وحی کے نکلتا ہی نہیں۔ وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی (النجم:۳، ۴) تو یہ بھی نہیں کہا کہ بلایاکیوں نہیں۔ اتنا کہنے سے بھی ایک طریقہ ایسا قائم ہو جاتا کہ آئندہ آنے والوں کے لیے اس لفظ سے بھی مشکلات پیدا ہو جاتیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا۔
تیسری بنیادی حد یہ ہے کہ شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، وہ نظر انداز نہ ہوں۔ شریعت کے جو اہم Objectives ہیں، ان کو اگر نظر انداز کر کے تفریح کی جائے تو وہ تفریح شریعت کی حدود سے متجاوز ہے۔ اسلام نے انسان کو کائنات کے اندر سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ خالق کائنات کے بعد سب سے اونچا مقام انسان کا ہے۔ انسان جسمانی طور پر تو بہت چھوٹی مخلوق ہے۔ آپ پوری کائنات میں ذرا غور کریں تو ہماری حیثیت وہ بھی نہیں ہے جو سمندر کے کنارے پر پڑے ریت کے کسی ذرے کی ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر ہماری حیثیت وہ بھی نہیں، لیکن اللہ نے قوت بے شمار رکھی ہے، صلاحیتیں بے شمار دی ہیں۔ آزادی اور فیصلے کی نعمت سے نوازا ہے، اچھے اوربرے کی تمیز کی صلاحیت دی ہے۔ یہ باقی مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اس کا درجہ اللہ نے اپنے بعد سب سے اونچا رکھا ہے۔ باقی ساری مخلوقات اس کے نیچے ہیں۔ یہ سب مخلوقات سے اوپر ہے اور خالق کائنات سے نیچے۔ ظاہر ہے جب درجہ اتنا اونچا ہے تو مقاصد بھی اتنے اونچے ہیں۔ خلافت ارضی سے اس کو نوازا ہے۔ خالق کائنات کی مرضی سے زندگی گزارنے کا یہ پابند ہے۔ اس کی مرضی کا عملی ترجمان بن کر اس کو دکھانا ہے کہ خالق کائنات جس طرح کا انسان چاہتا ہے، اس طرح کا انسان بننا ہے اور پھر دوسروں کے لیے اس کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جو حیثیت پیغمبر کی اپنی قوم میں ہوتی ہے، وہ حیثیت امت مسلمہ کی بقیہ اقوام میں ہے۔ یہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ: لتکونوا شھداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شھیداً (البقرۃ: ۱۴۳) تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، یعنی جو Relationship کی نوعیت تمہاری اور پیغمبر کی ہے، وہی نوعیت تمہاری اور بقیہ انسانوں کی ہے۔ اب اتنے اونچے مقام کو چھوڑ کر آپ نے تفریح کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جس میں یہ سب بھول جائیں کہ آپ کس کام کے لیے آئے تھے، کس کام کے لیے بھیجے گئے تھے تو یہ چیز ایک عام عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔
ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کمانڈر ان چیف پاکستان نیوی ایک بہت بڑامنصب ہے۔ بھاری ذمہ داری ہے، پاکستان کے پورے سمندروں کی نگرانی اور بہت سے کام ان کے ذمے ہیں۔ ان کو تفریح کا حق ہے، تفریح کرنی چاہیے، لیکن اگر نیوی کے دس جہاز تفریح کے لیے چلے جائیں اور دنیا کے سارے سمندروں کے بے آباد جزیروں میں جا کر شکار کھیلا کریں کہ جی شریعت نے تفریح کا حکم دیا ہے اور کچھ پتا نہ ہو کہ پاکستان میں پیچھے کیا گزر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس تفریح کو ناجائز سمجھتے ہوں گے۔ وہ بھی اس کو تفریح نہیں سمجھیں گے، ذمے داریوں سے تجاوز سمجھیں گے اور ذمے داریوں سے فرار قرار دیں گے۔ تو جو ذمے داری حکومت پاکستان نے پاکستان نیوی کے چیف کو دی ہے، اس سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی ہے، اس لیے ملت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو نظر انداز کر کے تفریح کرنا نامناسب و ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر نماز سب سے بڑا مقصد ہے۔
روز محشر کہ جاں گداز بود
اولین پرسش نماز بود
روز محشر جو جاں گداز ہوگا، اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب کوئی ایسی تفریح جس میں یہ پتا نہ چلے کہ نماز کب آئی، کب گئی، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے،یہ جائز نہیں۔
یہ تین بنیادی شرطیں ہیں جو شریعت نے تفریح کے لیے رکھی ہیں۔ اسراف وتبذیر سے اجتناب ہو، حیا کے حدود کے مطابق ہو، مقاصد شریعت سے تجاوز اور تجاہل نہ کیا جائے۔ ان حدود کے اندر جو تفریح بھی ہوگی، وہ جائز ہے، بغیر کسی رد وقدح کے آپ اسے جائز سمجھیں۔ ہم میں سے بہت سے حضرات کے مزاج میں شدت اور تیزی ہوتی ہے۔ بعض لوگ خالص دینی جذبے سے، کسی برے جذبے سے نہیں، دینی ومذہبی جذبے سے ہر جائز چیز کو بھی ناجائز کہنے لگتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے فرائض کا احساس اتنا شدیدہوتا ہے کہ ان کو ہر تفریح بھول جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن توازن کے خلاف ہے۔ اگر آپ امتحان دے رہے ہیں، فرض کیجیے آپ کا بی اے یا بی ایس سی کا امتحان ہورہا ہے اور بارہ بجے پرچہ ہونے والا ہے اور میں کہوں کہ وحدت روڈ کے فلاں اسکول میں آپ کا امتحان ہوگا، آپ وہاں چلے جایئے۔ اب کوئی تفریح یاد نہیں آئے گی۔ کوئی کہے کہ چلیں ہوٹل میں کھانا کھالیتے ہیں، تکے کھالیتے ہیں یا فلاں جگہ چلتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد نہیں آئے گا۔ آپ کو یہ خیال دامن گیر ہوگا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے ہاں جو اب دہی کا احساس اتنا تازہ ہو جتنا کہ آپ کوپرچے کا احساس تازہ ہے تو تفریح یاد نہیں رہتی۔ اسی لیے میں یہ کہتاہوں کہ یہ قابل احترام بات ہے۔ اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو امتحان کی جواب دہی کا احساس تازہ ہوگا، اسے کوئی چیز attract نہیں کرسکتی تو ایسے حضرات انتہائی احترام اور انتہائی عقیدت کے مستحق ہیں کہ جن کو آخرت کے امتحان کا احساس اتنا تازہ رہے کہ وہ ہر تفریح کو بھول جائیں، لیکن شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کا ذہنی رویہ ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ اگر کسی کا رہتا ہے تو اچھی بات ہے۔ ہر شخص کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یادداشت میں امتحان تازہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔
آپ نے حضرت حنظلہؓ کامشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت حنظلہؓ پریشانی میں تیز تیز تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکرصدیقؓ ملے، پوچھا کہاں جارہے ہو؟کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہوگیا۔ پوچھا، اچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سامنے ہے، جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے۔ کوئی چیز یاد نہیں آتی، صرف اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ جب واپس جاتا ہوں، کاروبار میں، تجارت میں، باغ میں، گھر میں تو وہ کیفیت نہیں رہتی تو یہ تو نفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور ہے اور آپ کے پیچھے کچھ اور۔ حضرت ابو بکرصدیقؓ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ نفاق ہے تو بہت بری بات ہے۔ چلیں، پوچھتے ہیں۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یارسول اللہ! یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوسکتا، یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ کبھی یہ کیفیت اگر رہے جو تم بتارہے ہو تو فرشتے آپ کے ہاتھ چومنے لگیں۔ گویاحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ چیز مطلوب نہیں کہ ہر وقت آپ پر یہ کیفیت طاری رہے اور نہ ایسا ہوتا ہے۔ اگرکسی پر طاری رہتی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا معاملہ خالص اللہ کے ساتھ ہے، لیکن بقیہ انسان ایسے ہیں کہ ان میں جب تفریح کا جذبہ پیدا ہو تو تفریح بھی کریں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرز عمل کو جو انہوں نے اختیار کیا ہے، جو انتہائی استثنائی ہے، وہ ہر شخص اختیار کرے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ہر شخص تفریح بھی چاہتا ہے، ہر شخص کے بعض اور تقاضے ہیں، وہ ان کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے جسمانی تقاضے بھی ہیں، مادی اور اقتصادی ہر قسم کے تقاضے ہیں، ان کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ توازن اور اعتدال کے بغیرشگفتگی ہوہی نہیں سکتی۔ شگفتگی اعتدال کا لازمی تقاضا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہؓ کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان دوڑ لگا رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ دوڑ کا مقابلہ کریں؟ آپ نے کہا چلو۔ مقابلہ کیا، دوڑ لگائی۔ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر کم ۵۷، ۵۸ سے کم نہیں تھی اور دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ اور اس کے قرب وجوار کے کم از کم ایک تہائی پر آپ کی حکومت تھی اور آپ کے پیروکاروں کی تعداد، جو اپنی زندگی کا محور ومرکز آپ کو مانتے تھے، اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرور تھی۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک معمولی مسجد کا مولوی، ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر، ایک کلاس کا ٹیچر اس طرح کرنے لگے تو سمجھتا ہے کہ میرا بھرم ختم ہو جائے گا اور لوگ کیا کہیں گے۔ میری ایک Dignity ہے یعنی پچاس چیزیں آدمی سوچتا ہے، ایک تصنع کاہالہ اپنے اوپر طاری کردیتا ہے۔ لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ رویہ Openness کے خلاف ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ایک بے تکلفی کا تعلق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہؓ کا بدن ہلکا تھا، عمربھی کم تھی، وہ آگے نکل گئیں اور کہا کہ دیکھا، ہرادیا! اس کے کچھ عرصے بعد پھر ایک مرتبہ سفر پر جانے کا اتفاق ہوا۔ پھر ایسے موقع پر دیکھا کہ لوگ دوڑ لگارہے ہیں تو کہا کہ آو دوڑ لگائیں۔اب حضرت عائشہؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا: ھذہ بتلک۔ یہ اس دن کا بدلہ ہوگیا۔ مثالیں اور بھی ذہن میں ہیں جو دی جاسکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان میں حس مزاح (Humor) بھی رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حس مزاح تو ضرب المثل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اگر آپ نے پڑھے ہوں۔ اگر نہ پڑھے ہوں تو ضرور پڑھیں۔ ترمذی کی بڑی اچھی کتاب شمائل ترمذی ہے جس کا اردو اور انگریزی ترجمہ دستیاب ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے بارے میں، آپ کے حلیہ مبارک، لباس، عادات، خصائل کے بارے میں بڑی معلومات جمع کی ہیں اور ایک بڑے مستند ترین محدث وقت کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں جتنے اقوال وواقعات جمع کیے گئے ہیں، بڑے مستند ہیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ کے دس سال بلکہ مکہ مکرمہ کے تیرہ سال دیکھیں تو یہ انتہائی کرائسز کا زمانہ ہے۔ کرائسزاوربحران کے جو بھی پہلو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کسی علاقے میں ہنگامی حالات کے جو بھی اسباب آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے بیک وقت موجود تھے کہ چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے، ہر تین چار مہینے بعد حملہ ہو رہا ہے، ہر تین چار ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج لے کر نکلنا پڑتا ہے اور اوسطاً ہر چار ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر فوج لے گئے ہیں، دفاع کرنے یا فتنے یا خطرے کا سدباب کرنے کے لیے۔ کبھی باہر سے کوئی سازش ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کوئی آرہا ہے، کچھ لوگ آپ کو شہید کرنے آرہے ہیں، لیکن ان سارے ہنگامی حالات اور خطرات کے باوجود آپ کی جو حس مزاح ہے، وہ اسی طرح موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص توازن اور اعتدال کی معراج پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اوپر توازن اور اعتدال کا تصور انسان کے ذہن میں نہیں آتا۔ بعض اوقات بچوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بچے دوڑ لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ لگا رہے ہیں۔ کبھی صحابہ کرامؓ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرامؓ میں جاکر دیکھا کہ شعر وشاعری ہورہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعر وشاعری سننی شروع کردی۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میاں! یہ کیا لغو حرکت ہے۔ دیکھتے نہیں کہ ہم آگئے ہیں، تب بھی شعر وشاعری ہورہی ہے! آپ بھی شعر سن رہے ہیں، لیکن اگراس میں کوئی بات شریعت کے خلاف ہوگئی تو آپ نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ ٹھیک نہیں۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ خوشی منارہے ہیں، بچیاں ڈھولک پر گا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاکر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بچی نے گاتے گاتے ایک جملہ کہا کہ: وفینا نبی یعلم ما فی غد (بخاری،کتاب المغازی، باب ۱۲، رقم ۴۰۰۱)۔ اور ہم میں ایک نبی بھی ہیں جو کل کا حال جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ بات مت کہو۔ کل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی عقیدے پر بات آئی تو فوراً اسی وقت ٹوک دیا، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ آئے تو بیٹھے رہے اور وہ گاتی رہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ آئے توبچیاں اٹھ کر چلی گئیں۔ حضرت عمر فاروقؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے آنے پر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروقؓ کو نہیں روکا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم اتنے سخت کیوں ہو؟ اور ان بچیوں کو نہیں روکا کہ تم کیوں بھاگتی ہو؟ آپ دیکھیں کہ جس آدمی کے مزاج میں شدت ہے، وہ شدت دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس شدت کو نہیں روکا۔ اس میں اگر حضور کہتے کہ مت روکو تو پھر وہی بات ہوتی کہ ہمیشہ کے لیے ممکن ہے۔ آگے چل کر کوئی اعتدال سے بڑھ جانے والا ہو تو ممکن ہے بعض اوقات آپ کسی مصلحت سے روک دیں۔ یہ چیز جائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، لیکن آپ ماں ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اس وقت بچے کو اس میں لگنے دیا گیاتو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس وقت اس جائز کام کو روک دینا چاہیے، ممکن ہے اس سے غلط عادت پیدا ہوجائے۔ فرض کیجیے محلے میں کبوتر باز رہتے ہیں، کبوتر بازی کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ ایک کبوتر لے آیا، چھوٹا کبوتر پالنا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اس وقت روک سکتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ محلے والوں کے ساتھ مل کر غلط عادت پڑجائے گی۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضور عمر فاروقؓ کو روک دیتے کہ دیکھو منع مت کرو تو یہ ہمیشہ کے لیے قانون اور شریعت کا حکم بن جاتا کہ اگر کوئی جائز تفریح کے کسی کام میں مصروف ہو، کسی بھی مصلحت سے اس کو روکا نہیں جاسکتا۔ اب مصلحت سے آپ روک سکتے ہیں، حضرت عمرؓ کی سنت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بچیوں کو گانے سے روکا اور نہ حضرت عمر فاروقؓ کو منع کرنے سے روکا۔ دونوں کو اپنی اپنی حالت پر رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ تشریف لائے جو سو فیصد مزاج شناسِ رسول تھے، انہوں نے نہیں روکا۔ حضرت عمرفاروقؓ جن کے مزاج میں سختی تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ واشدھم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں میرے صحابہ میں سب زیادہ سخت عمرؓ ہیں۔ انہوں نے روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ اسی طرح کے واقعات اور مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اظہار مسرت اور خوشی کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں، جب تک وہ شریعت کے حدود کے اندر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں روکا۔ انسان خوشی کے موقع پر چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو۔ انسان خوشی کے موقع پر چاہتا ہے کہ اس کی خوراک اچھی ہو، اپنے دوستوں کو بلائے، اپنے احباب کو بلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے، لیکن اب اس بات کا امکان موجود تھا کہ جب لوگ خوشی ومسرت کے موقع پر دوست واحباب کو بلائیں گے تو انسان کا مزاج آپ نہ بھولیے، انسان کا مزاج بدلتا نہیں ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ مادی مفادات چاہتا ہے، ،انسان کا مزاج یہ ہے کہ دولت چاہتا ہے، صاحبان اقتدار کے قریب ہونا چاہتا ہے۔
بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اِتراتا
وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے
جو شہ کا مصاحب ہوتا ہے، وہ اِتراتا بھی ہے۔ تو اس میں یہ رجحان بھی موجود ہے کہ جی بڑے آدمیوں کو بلاؤ، چھوٹے آدمیوں کو نظر انداز کردو تو آپ نے جہاں خوشی کے اظہار کی اجازت دی اور تلقین کی کہ لوگوں کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، لوگوں کو جمع کرو، وہاں یہ بھی فرمایا کہ بدترین دعوت ہے وہ جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے، لیکن غریبوں اور ناداروں کو چھوڑ دیا جائے۔
عیدالاضحی کے موقع پر قربانی کا حکم دیا۔ اس میں آپ دیکھیں توازن کیا ہے۔ ایک تہائی اپنے لیے رکھو، ایک تہائی دوست احباب کو بھیجو اور ایک تہائی آس پاس کے جوضرورت مند ہوں، نادار ہوں، چاہے دوستی رشتے داری نہ ہو، ان کو بھیجو۔ تو آپ دیکھیں کہ تینوں یکساں سطح پر ہیں۔ اپنی ذات بھی، دوست احباب بھی اور شہر کے نادار اور کمزور لوگ بھی۔ یہ خوشی کے موقعے پر اجتماعیت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تفریح جس سے طبقاتیت کو فروغ ملے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اور وہ تفریح جس سے طبقات ہم آہنگ ہوں، مسلمانوں میں ہم آہنگی پیدا ہو، بستی میں یکجہتی پیدا ہو،وہ تفریح اسلام کے تصور کے مطابق ہے، اسلام کے تصور سے ہم آہنگ ہے۔
دوسری چیز جو یاد رکھنے کی ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ثقافتی چیز ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ بات کہ یہ ثقافتی چیز ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اسلام کا ہر چیز سے تعلق ہے۔ اسلام تو ہر چیز کے بارے میں راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ثقافت کے بارے میں بھی کرتا ہے۔ اگر ثقافت میں کوئی ایسی چیز ہے جو مشرکانہ اورکافرانہ پس منظر رکھتی ہے،جیسا کہ میں نے مثالیں دیں کہ پیلے رنگ میں ویسے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر پیلے رنگ میں یہ عقیدہ ہو کہ اس میں دیوی اترتی ہے، لہٰذا مجھے پیلے رنگ کے کپڑے پہننے ہیں تو پیلے رنگ میں بہت کچھ ہے۔ اگر ویسے ہی کسی کوپیلا رنگ اچھا لگتا ہے اور وہ بسنت کے علاوہ بھی پیلے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے یا پہنتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر بسنت کے ہی دن پیلا رنگ پسند آتا ہے، اور کسی دن پسند نہیں آتا پھر معلوم ہوتا ہے کہ بات محض پسند کی بات نہیں، کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مقامی ثقافت ہے، اس کا جو مظہر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ محض ثقافتی چیز ہے، وہ کیاہے؟ اگر اس کے پیچھے محض کسی قوم کا رواج ہے، اس کے پیچھے کسی غیر مذہب کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مشرکانہ، جاہلانہ اور کافرانہ تصور نہیں ہے تو اس ثقافت کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مثال کے طور پر عید کے موقع پر لوگوں میں سویاں بنانے کا رواج ہے تو سویاں بنانے کا نہ کوئی مذہبی پس منظر ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی ملحدانہ، مشرکانہ اور کافرانہ تصور ہے۔ یہ محض رواج ہے۔ ممکن ہے شروع میں کسی طبی ضرورت کے تحت اختیار کیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں رمضان میں افطار کے وقت پکوڑے بنانے کارواج ہے، کئی اور ملکوں میں نہیں ہے۔ اب یہ طبی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے ایک خاص موسم میں پورادن بھوکا رہنے کے بعد چنا شاید مفید رہتا ہو، اس طرح رواج ہوگیا۔ بعض عرب ملکوں میں اس کا رواج نہیں، کسی اور چیز کا رواج ہے۔ میں نے بچپن میں ہمیشہ اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ کبوتر بڑا گرم ہوتا ہے اور کبوتر کا گوشت کبھی ہمارے گھر میں کسی نے بنایا نہیں کہ اگر کسی نے کھایا تو نکسیر پھوٹ پڑے گی اور دانے نکل آئیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہوجائے گا۔ کافی عرصہ پہلے، غالباً ۱۹۹۰ء میں مجھے مراکش جانے کا اتفاق ہوا۔ رمضان کامہینہ تھا۔ ایک جگہ جب میں گیا تو اسی دن کسی بڑے آدمی کے ہاں افطار تھا تو ملازمین بڑی بڑی دیگوں میں سوپ لے کر آئے۔ وہ کبوتر کی یخنی تھی اور انھوں نے بڑے بڑے پیالے میںیخنی بھر کر دی اور دو دو کبوتر بھی ڈالے۔ اب میں بہت ڈرا کہ گرمی کا موسم بھی ہے، روزہ بھی ہے اور یہ بھی سنا تھا کہ روزے میں خشکی ہو جاتی ہے تو نکسیر پھوٹ جائے گی۔ میں نے پیالے کو رکھ دیا، لیکن پھر سوچا کہ یہ پانچ سو آدمی کھارہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہوگا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا، چنانچہ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑی سی یخنی پی لی اور کبوتر نہیں کھایا۔ اگلے دن ایک کبوتر کھایا اور دوسرے دن دونوں کبوتر کھالیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ نکسیر پھوٹی، نہ دانے نکلے اورنہ کوئی پریشانی ہوئی۔ اب یہ محض رواج ہے۔ میں نے دیکھا کہ مراکش میں افطار کے وقت یخنی ہر جگہ ہوتی ہے۔ غریب، امیر سب کے پاس۔ دوکان میں جائیں تو کبوتر کی یخنی ملے گی، بادشاہ کے پاس جائیں تو کبوتر کی یخنی ملے گی۔
اس طرح کی ثقافت ظاہر ہے، ہر قوم میں الگ الگ ہوتی ہے۔ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، مسلمانوں نے کبھی اس کو ختم نہیں کیا۔ یہ ثقافتیں آج تک چلی آرہی ہیں۔ اسلام جس علاقے تک گیا، وہاں کے رسم ورواج کو صحابہ نے بھی اختیار کیا، وہاں کے اچھے طریقوں کوصحابہ نے بھی اپنایا۔ کبھی کسی صحابی یا تابعی نے نہیں کہا کہ اہل شام، تم فلاں قسم کا کھانا بند کر دو اور ہمارے جیسا کھانا کھانا شروع کر دو یا ہمارے جیسا لباس اپنا لو۔ لباس الگ الگ رہے۔ اہل شام کا الگ تھا، سینٹرل ایشیا والوں کا الگ تھا، اب بھی الگ ہے۔ جزیرہ عرب والوں کا الگ تھا، ایرانیوں کا الگ تھا۔ اس میں اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف تھی تو اس کی نشان دہی کر دی گئی کہ یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے۔ مثلاً مرد ریشم پہنتے ہیں، یہ درست نہیں ہے یا آپ کا لباس مکمل طور پر ساترنہیں ہے تو ستر کا تقاضا ہے کہ اسے پورا کریں۔ اس طرح ضروری تبدیلی تو ہوتی رہی، لیکن اس طرح کی مقامی روایات کو جو شریعت کے متصادم نہیں تھیں، کبھی کسی نیختم نہیں کیا، بلکہ ان کواختیار کیا اوران کو پروموٹ (Promote) کیا۔ سب سے پہلی شرط تو مقامی ثقافت کے بارے میں یہ ہے۔
دوسری شرط مقامی ثقافت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی وحدت سے متصادم نہ ہو۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اسلام میں تہوار موسم کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ موسم ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کہیں سردی ہوگی، کہیں گرمی ہوگی، کہیں بہار ہوگی۔ اگر موسم کے حساب سے اسلام میں تہوار ہوگا تو پوری دنیا میں نہیں ہوسکتا، اس لیے کوئی ایسا تہوار یا مقامی ثقافت یا مقامی رواج جس سے ملت مسلمہ کی وحدت ختم ہوجائے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی وحدت قرآن کریم کی نص قطعی کی رُو سے ضروریات دین میں سے ہے: ان ھذہٖ امتکم امۃ واحدۃ (الانبیاء:۹۲)۔ یاد رکھو، بلاشک وشبہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ امت کی وحدت میں خلل نہ پڑنے پائے۔ لہٰذا کوئی مقامی ثقافت جو امت مسلمہ کی وحدت متاثر کرے، شرعاً قابل قبول نہیں ہے۔
تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ثقافت کہتے ہیں، اس کا تعلق عقائد، عبادات اور ان معاملات سے نہ ہو جن کے بارے میں شریعت نے واضح ہدایات دی ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، وہ چار ہیں :
۱۔ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ عقائد میں کوئی مقامی یا غیر مقامی ثقافت قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ وہی قابل قبول ہے جو قرآن پاک اورسنت میں ہے۔
۲۔ عبادات ہیں۔ عبادات میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ صرف وہ عبادت قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کی ہرقسم بالکل بدعت ہے۔ اس میں کوئی تامل کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ عبادت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی یا جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے نہیں ملتی، وہ عبادت، عبادت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جن کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے، اس میں کوئی External element داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اضافے کی اجازت نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میرا تو اللہ کے آگے جھکنے کو بڑا جی چاہتا ہے۔ دو سجدوں سے تشفی نہیں ہوتی، میں دس دس سجدے کیاکروں گا۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔
تیسری چیز ہے معاملات اور لین دین۔ لین دین میں شریعت نے جو احکام دیے ہیں، عمومی احکام ہیں، عمومی ہدایات ہیں۔ تفصیلات انسانوں پر چھوڑ دی ہیں۔ لیکن اگر مقامی ثقافت کا تعلق معاملات سے ہے تووہ شریعت کی ان حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ جن معاملات کی تعلیم شریعت نے دی ہے، اس کے اندر وہ مقامی ثقافت ہو، اس کے باہر نہ ہو۔ مثال کے طور پر شریعت نے کہا ہے کہ کسی کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر نہ خریدو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم (النساء :۲۹) یہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے، شریعت کا حکم ہے، لہٰذا کوئی ایسا مقامی رواج جس سے زبردستی کسی سے پیسہ نکالا جائے یا اس کے مال وجائداد کو ہتھیا لیا جائے، جائز نہیں ہے۔
میں مثالیں دوں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی، لیکن شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں گھیر لیتی ہیں کہ بہنوئی سے جوتا چھپائی لینی ہے۔ بے چارہ پتہ نہیں پیسے لایا کہ نہیں لایا۔ شوق سے اور خوشی سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ جوتا چھپائی کے نام سے دے یا ٹوپی چھپائی کے نام سے دے۔ مجھے پتہ نہیں جوتا چھپائی کاکیا پس منظر ہے،کیا بیک گراؤنڈ (Background) ہے! ممکن کہ اس کا بھی کوئیبیک گراؤنڈ ہو، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں زبردستی یا کسی شخص کی مرضی کے خلاف اس سے پیسے یا رقم لی جاتی ہے تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ (مسندالامام احمد بن حنبل ج ۶، ص: ۳۰۹، رقم ۲۰۹۷۱)۔ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں، سوائے اس کے وہ اپنی خوشی سے، باہمی رضا مندی اور طیب نفس سے دے رہا ہو۔ اپنی پوری خوشی کے ساتھ دے رہا ہو تو وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ یقین کرنا کہ کہاں خوشی سے دے رہا ہے، کہاں مجبوری میں دے رہا ہے، یہ اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا کوئی ایسا رواج جس میں زبردستی کسی کی رقم ہتھیا لی جائے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔
۴۔ چوتھی چیز عادات ہے۔ عادات میں شریعت میں بہت آزادی ہے۔ کھلا چھوڑا ہے۔ ہر قوم کی عادات ورواج ہوتے ہیں۔ کسی کے یہاں چادر اوڑھنے کا رواج ہے، کسی کے ہاں تہ بند باندھنے کا رواج ہے، کسی کے ہاں چارپائی پر سونے کا رواج ہے، کسی کے ہاں فرش پر سونے کا رواج ہے، کسی کے پاس کوئی کھانا مروّج ہے، کسی کے پاس کوئی کھانا مروّج ہے۔ کوئی چاول کھاتا ہے، کوئی کدو کھاتا ہے۔ یہ سب عادات ہیں۔ مختلف قوموں کی عادات ہیں جن کا تعلق جغرافیے سے، تاریخ سے، مقامی حالات سے، اقتصادی وسائل سے ہوتا ہے۔ اس میں شریعت نے بالکل آزادی دی ہے کہ اگر کوئی چیز شریعت کی نص قطعی کے خلاف نہیں ہے تو آپ جو جی چاہے کریں، آپ کو کھلی آزادی ہے کہ اسے اختیار کریں۔ مقامی ثقافت اورعادات کے باب میں اس کی کھلی گنجائش ہے، جیسا کہ میں نے عید کے موقع پر سویوں کی مثال دی۔
یہ وہ بنیادی ہدایات اور اصول ہیں جو شریعت نے تفریح کے بارے میں دیے ہیں۔ ان حدود کے اندر جو تفریح یا تہوار ہوگا، وہ منانا جائز ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں تفریح اور تہوار منانے کے بارے میں مثبت ہدایات کیا ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جن میں منفی چیزوں سے روکا گیا ہے۔ جو چیز شریعت نے خود بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزوں کو الگ الگ دیکھیں۔ پہلے دیکھیں تفریح اور اس کے بعد دیکھیں تہوار۔ تفریح سے مراد وہ سرگرمی ہے جو وقتاً فوقتاً انسان انفرادی طور پر کرتا ہے۔ آپ آؤٹنگ (outing) کے لیے چلے گئے، پکنک (Picnic) کے لیے چلے گئے۔ یہ تفریح ہے۔ دوستوں کی دعوت کرلی، مہمانوں کو بلالیا، یہ چیزیں تفریح ہیں۔تہوارسے مراد عیدالفطر اور عیدالاضحی ہے۔
پہلے تفریح کو دیکھ لیں۔ تفریح کے بارے میں شریعت نے جو ہدایات دی ہیں، پہلے ان کے بارے میں وہ تین ہدایات سامنے رکھیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ صحابہ کرامؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کو مقاصد عالیہ سے ہم آہنگ کر لیا۔ اسلام کے جو Higher objectives ہیں، امت مسلمہ کے جو مقاصد عالیہ ہیں، ان کو اور تفریح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کرلیا۔
تفریح کی تین عام شکلیں ہیں۔ ان میں پھر مختلف ورائیٹیز ہیں، لیکن بڑی بڑی شکلیں تین چار ہیں۔ تفریح کی ایک شکل یہ ہے کہ لوگ سیر وتفریح کے لیے جاتے ہیں۔ کسی اور ملک میں تفریح کے لیے چلے گئے، شہر کے کسی مقام پر چلے گئے، شہروالے گاؤں کی تفریح کے لیے چلے گئے، گاؤں والے شہر میں گئے، ریگستان گئے، پہاڑوں پر گئے، دریا یا سمندر کے کنارے گئے۔ یہ ایک عام تفریح ہے جو ہر شہری کرتا ہے اور ہرانسان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے علاقے سے باہر نکل کر سیر وتفریح کرے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گونگے، اندھے، بہرے آدمی کی طرح جیسے گئے تھے، ویسے واپس آگئے۔ نہ کسی اچھائی کا پتہ چلا، نہ کسی برائی کا پتہ چلا۔ انسان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تفریح یہ ہے کہ جیسے مکھی ہوتی ہے، اس کو گندگی ہی نظر آتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی۔ خوشبو، تازہ پھول رکھے ہوں تو مکھی وہاں نہیں بیٹھے گی۔ ایک نکتہ گندگی کا ہو تو ساری مکھیاں وہاں جمع ہو جائیں گی۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو سیر وتفریح میں گندگی نظر آتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی۔ اسلام نے ایسی تفریح کو پسند نہیں کیا۔ جاتے ہیں تو نامحرم عورتوں کو ہی تاڑتے ہیں کہ یہاں کوئی نامحرم عورت ملے۔ یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی خلاف شریعت کام اور سرگرمی ہو تو پتہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ منفی تفریح ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکھی کا مزاج ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تفریح کے لیے جاؤ تو سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین (النمل: ۶۹) جب جاؤ تو ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ یہ دیکھو کہ پچھلی اقوام کا عروج وزوال کیسے ہوا۔ جو قومیں مٹ گئیں، ان کے آثار باقی ہیں۔ ان کے آثار محض تاریخی چیز کے طور پر نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کو زوال کیوں ہوا؟ ان کی غلطیاں کیا تھیں؟ ان کی کمزوریاں کیا تھیں؟ گویا تاریخ کو سیر سے وابستہ کر دیا کہ اس سیر کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اسی نظریے کے ساتھ سیر کے لیے جاؤ، ہر جگہ جاؤ۔ بعض جگہ ایسے تاریخی اور عبرت انگیز مقام نہیں ہوتے تو مظاہر کائنات کو دیکھو۔ (الی الارض کیف سطحت)۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بچھایا۔ شہر میں آپ دیکھیں تو اس کو احساس نہیں ہوگا کہ الی الارض کیف سطحت۔ لیکن ریگستان میں کسی پہاڑ کے قریب جا کر دیکھیں تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسے بچھایا۔ واقعی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بچھایا۔ الی الابل کیف خلقت۔ اور نہیں تو کسی جانور پر غور کرو کہ اللہ نے اسے کیسا پیدا کیا۔اللہ کی حکمت کیا ہے۔ کسی بھی چیز پر غور کرنا شروع کردیں۔
ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک کتاب دکھائی جو ایک ماہر شخص نے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے طور پر ایک آلو پر لکھی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی ہر چیز پر غورکرنے سے اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے۔ آلو کو سامنے رکھ کر ایک بڑی موٹی کتاب لکھی تھی کہ آلو میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آلو میں پوری کائنات موجود تھی۔ اس کو مائیکرو اسکوپ کے ذریعے دیکھا تو جیسے دنیا کے اندر نہریں، سمندر اور جانورموجود ہیں، اس آلو کے اندر موجود تھے۔ چھوٹے مائیکرو اسکوپ کو اس آلو کے اندر لگا کردیکھاتو پورا کرۂ ارض اس آلو میں موجود ہے۔ اللہ کی مخلوقات اور ان میں تعارض اور تناسل، نہریں، پانی اورغذائیں اور پودے، سب کچھ اس چھوٹے سے آلو میں موجود تھا۔ جب انہوں نے مجھے وہ کتاب دکھائی اور مجھے اس کے بارے میں بتایا تو سچی بات یہ ہے کہ غیر معمولی انداز میں مجھے قرآن مجید کی وہ آیتیں یاد آئیں کہ جس چیز میں غور کرو گے، اللہ کی قدرت کو پاؤ گے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی تعلیم ہے۔ اس لیے جب انسان سیر کے لیے جائے گا تو ایک لمحہ بھی مقاصد عالیہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہیں گے۔ مقاصد عالیہ اس کی نظروں میں رہیں گے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی توحید، کائنات کی عظمت، اپنا مقام اور ذمے داری اس کو یاد رہیں گی۔ تفریح بھی ہورہی ہے، مقاصد عالیہ سے بھی وابستگی ہے اور خود بخود ایک سبق بھی مل رہا ہے۔
دوسری چیز جو تفریح کے طور پر انسان کرتا ہے، وہ آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک مثبت چیز میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ مقابلہ اچھی چیز ہے، لیکن مقابلہ کسی برائی میں نہ ہو، کسی منفی چیز میں نہ ہو، مقابلہ کسی تباہ کن چیز میں نہ ہو۔ مقابلہ کسی مثبت اور خیر کی چیز میں ہو: وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون (المطففین:۲۶)۔ خیر کے کاموں میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص خطاط ہے۔ آپ اس سے بڑھ کر خطاط بننا چاہیں۔ ایک شخص اچھا قاری ہے، آپ اس سے بڑھ کر اچھا قاری بننا چاہیں۔ ایک شخص اچھا ماہر ریاضیات ہے، آپ اس سے بڑھ کر ماہر ریاضیات بننا چاہیں۔ ایک شخص اچھا معمار ہے، آپ اس سے اچھا معمار بننا چاہیں۔ جو چیزیں بھی مثبت ہیں، تعمیری ہیں، اس دنیا کے بارے میں ہوں یا آخرت کے بارے میں ہوں یا دین کے بارے میں ہوں، ان میں مقابلہ اچھی بات ہے۔ ایک بہن اچھی cook ہے، دوسری بہن اس سے اچھی cook بننا چاہتی ہیں۔ ایک بہن کو بریانی اچھی بنانی آتی ہے، دوسری بہن اس سے اچھی بریانی بنانا سیکھ لے۔ اس میں مقابلہ کرنے میں حرج نہیں، مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہر اچھی، مثبت اور تعمیری سرگرمی میں صحت مندانہ مقابلہ، یہ قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل مطابق ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان صحابہ میں اس طرح کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر وقت دشمنوں کا خطرہ تھا، ہر وقت مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ آٹھ سالوں میں ۸۲ غزوات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا۔ اب اگر calculate کریں تو ہر ماہ یا ڈیڑھ ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا۔ اسی طرح ایمرجنسی کی بھی کیفیت تھی اور یہ کیفیت تھی کہ رات کو اگر کہیں سے شور کی آواز آئے تو لوگ سمجھتے تھے کہ باہرسے کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ آٹھ سال کا عرصہ تقریباًہر لمحہ ایمرجنسی کا زمانہ رہا۔ اس لیے اس کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ کرامؓ کوجہاد کی تربیت دیں، چنانچہ نوجوانوں میں جب مقابلے ہوتے تھے تو تیر اندازی کے ہوتے تھے یا گھوڑ دوڑ کے ہوتے تھے یا اونٹ دوڑ کے ہوتے تھے یا تلوار بازی کے ہوتے تھے یا اسی طرح کے مردانہ مقابلے ہوتے تھے کہ جس میں کھیل بھی ہو، تفریح بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتنے والے کو انعام بھی دیا کرتے تھے کہ جو جیتے گا، اس کو انعام بھی دیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعمیری کاموں میں صحت مندانہ مقابلہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ قرآن مجیدکے مطابق بھی ہے، سنت کے مطابق بھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقابلوں کا اہتمام کیاہے۔
امہات المؤمنینؓ اور صحابیاتؓ میں اور قسم کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ کھانا پکانے کے، سینے کے، گنتی سیکھنے کے، حساب سیکھنے کے یا اس زمانے کے گھریلو حساب سے ہوم اسٹڈی (Home study) یا ہوم اکنامکس (Home Economic) کہہ سکتے ہیں، وہ صحابیات میں رائج تھی اور وہ صحابیات سیکھتی تھیں ۔ایک دوسرے سے علم قرآن کا مقابلہ تو تھا ہی۔ علم حدیث کا مقابلہ بھی تھا، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے جو خالص دنیوی علوم کی چیزیں تھیں جیسے کھاناپکانا یا سینا، ان میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا سلسلہ تھا۔
ایک تیسری چیز ہوتی ہے، کھیل کود۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ہم باہر پکنک کے لیے جارہے ہیں، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لیں۔ یرتع ویلعب (سورۃ یوسف :۱۲) ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور جنگل میں کھائے پیے۔ پیغمبر نے اجازت دے دی۔ قرآن پاک کی تفسیر کا یہ اصول ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی جو شریعت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اور اس کی منسوخی کی کوئی ہدایت یا Indication نہیں ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ ہر وہ حکم جو سابقہ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں یا سنت میں اور صرف قرآن وسنت میں آیا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ یہاں غلط فہمی نہ ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے کہیں تقریر کی تو کسی نے یہ بات کہی کہ تورات اور انجیل کو بھی میں نے شریعت کا ماخذ بنا دیا ہے۔ قرآن پاک میں اور سنت میں سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے بارے میں جو فرمودات نقل ہوئے ہیں، اگر وہ فرمودات کسی منسوخی کی ہدایت کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ ہماری شریعت کا حصہ ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: وکتبنا علیہم فیھا ان النفس بالنفس والعین بالعین (المائدۃ:۴۵) ہم نے یہودیوں پر فرض کیا تھا تورات میں کہ نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ بعینہ ہمارے لیے حکم ہے، حالانکہ تورات کے حوالے سے قرآن پاک میںآیا ہے، لیکن چونکہ منسوخی نہیں آئی، اس لیے ہمارے لیے حکم ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ایک پیغمبر کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کھیل کود کی اجازت دے دی۔ اس لیے کہ بارہ تیرہ سال کی عمرمیں ایک خاص اسٹیج ہوتا ہے جس میں زیادہ فلسفہ آپ ان کے دماغ پر لاد نہیں سکتے۔ یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ بعض ماں باپ کو میں نے دیکھا کہ چھ یا سات سال کا بچہ ہے، اس کے دماغ میں ٹھونس رہے ہیں کہ آپ کو کیا بننا ہے۔یہ بچے کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کو کھیلنے دیں۔ کھیل کود سے جسمانی طور پر اس کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیز انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے مطابق ہے۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بچے کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے جتنی تربیت دی جاسکتی ہے، اتنی تربیت آپ دیں۔ بچیوں کی تربیت اور انداز کی ہوگی، لڑکوں کی اور انداز کی ہوگی۔ یہ ہر ماں باپ اپنے طور پر طے کرلیں۔ اپنے بچوں کے لحاظ سے طے کریں کہ ان کے بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے ذہن میں بچے کے مستقبل کے بارے میں کیا آرزوئیں اور تمنائیں ہیں اور اس کے حساب سے بچے کو تیار کریں۔
یہ تین تفریحیں ہیں جن کو اسلام نے اپنے تمام مقاصد سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ ان تفریحوں پر آپ بقیہ تمام تفریحوں کو قیاس کرسکتے ہیں۔ تفریح کی جو بھی شکل آپ ایجاد کریں یا جو بھی قوم ایجاد کرے، وہ انہی حدود کی پابند اور اسی نقشے کے مطابق ہو۔
تہوار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکل قوم عید وھذا عیدنا۔ ہر قوم کی ایک عید یا تہوار ہوتا ہے اور یہ ہماری عید اور تہوار ہے۔ تہوار کے بارے میں، میں نے عرض کیا کہ مختلف اقوام میں مختلف چیزوں کا رواج ہے۔ کہیں بادشاہ تخت پر بیٹھا تو تہوار ہے، کہیں جنگ میں فتح ہوئی تو تہوار ہے، کوئی دیوتا کے نام پر تہوار ہے، کہیں موسم کے بدلنے پرتہوار ہے۔ اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی۔ اسلام نے جو تہوار رکھے ہیں، وہ ایسے تہوار ہیں، ان کی Timing ایسی ہے کہ پوری امت مسلمہ اس کو ایک وقت میں مناسکتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں تو بہار شروع ہوگئی، وہاں بیس دن کے بعد شروع ہوگی، فلاں جگہ سرے سے بہار کا موسم آئے گا ہی نہیں۔ صرف سردی کا موسم ہے یا گرمی کا۔سائبیریا میں نہ خزاں کا تصور ہے، نہ سردی کا نہ گرمی کا۔ تو فرض کیجیے کہ اسلام بہار سے نو روز کو تسلیم کرتا ہے کہ نو روز سے عید ہوا کرے گی تو سائبریا کے مسلمان کیا کرتے؟ ان کے لیے تو نہ نوروز ہے نہ تین روز، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جو سارے مسلمانوں کے لیے قابل عمل نہ ہو۔ یہ دوتہوار جو اسلام نے رکھے ہیں (تہوار کا لفظ میں صرف مناسبت سے بول رہاہوں، ورنہ عید کا لفظ بولنا چاہیے) اس میں سے ایک عید الفطرہے اور ایک عید الاضحی۔ یہ دو وہ تہوار ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔
خلاصۂ کلام
گفتگو کا خلاصہ بیان کردیتا ہوں کہ اسلام نے تفریح کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے دو تہوار فراہم کیے ہیں۔ اسلام نے تفریح کو اخلاقی اور دینی حدود کا پابند قرار دیاہے، تفریح کے وہ آداب دیے ہیں جو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے ضامن ہوں۔ تفریح میں ان حدود سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے جو دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ جو تہوار دوسری قوموں میں رائج ہیں، وہ سارے کے سارے ایسی بنیادوں پر استوار ہیں جو ملت مسلمہ کی عالمگیریت کے خلاف ہیں یا عقیدۂ توحید کے خلاف ہیں، اسی لیے اسلام نے ان تہواروں کو قبول نہیں کیا۔ ان سے یا عالمگیریت متاثر ہوتی ہے یا عقیدہء توحید متاثر ہوتا ہے، اس لیے ایسے تہوار دیے ہیں جن سے عقیدۂ توحید بھی بدرجہ اتم مکمل رہتاہے اور عالمگیریت بھی بدرجہ اتم emphasize ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان غیر اسلامی تہواروں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ جب وہ خوشی منائیں تو شریعت کے حدود کے اندر منائیں، جب کسی تفریح کا بندوبست کریں تو شریعت کے حدود کے مطابق کریں۔ اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔
اسلام اور جدید تجارت و معیشت
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(جامعۃ الرشید کراچی میں تقریب تقسیم اسناد کے موقع پر ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا خطاب)
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
قابل احترام علماء کرام ! میرے انتہائی عزیز طلبہ اور دوستو!
سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان طلبہ کی خدمت میں مبارک با د پیش کرتا ہوں جو آج فارغ التحصیل ہوئے اور ایک ایسے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے جو امت مسلمہ تقریباً ایک سو سال سے دیکھ رہی تھی۔
برادران محترم! آج دنیاے اسلام کوجو مشکلات اور چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ دور جدید کی زبان میں، دور جدید کے محاورے میں اور دور جدید کے اسلوب میں قرآن مجید اور حدیث کو بیان کیا جائے۔ آج زبان بدل چکی ہے، محاروہ بدل چکا ہے، اصطلاحات بدل چکی ہیں اور اسلوب بدل چکا ہے، اس لیے آج کل کی زبان میں انسانوں تک اور آج کل کے لوگوں تک قرآن وسنت کی تعلیم کوپہنچانا ان تمام حضرات کے ذمے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علم سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اس نے جس نبی یا پیغمبر کو بھیجا، اس علاقے اور اس قوم کی زبان اور محاورے کے ساتھ بھیجا جو وہ قوم استعمال کرتی تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِہِ۔ (۱۴:۴) لسان میں محض لغت شامل نہیں ہے۔ لسان میں لغت بھی شامل ہے، محاروہ اور اسلوب بھی شامل ہے، طرز استدلال بھی شامل ہے اور وہ ثقافتی مظاہر بھی شامل ہیں جن کا تعلق زبان اور اظہار بیان سے ہوتا ہے۔ آج جس میدان میں شریعت کی تعلیم کو اس نئے انداز سے بیان کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اسلام کا قانون معاملات ہے۔
معاملات اور تجارت کے احکام کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی مذہب نے، تاریخ کے کسی نظریے نے اور کسی فلسفے نے معیشت وتجارت کو وہ مقام اور اہمیت نہیں دی جو اسلام نے دی ہے۔ دنیا کے کسی نظام نے معیشت اور تجارت کو اخلاق اور روحانیات سے اس طرح وابستہ نہیں کیا جس طرح اسلام نے ان دونوں کو وابستہ کر دیا ہے۔ دنیا کے کسی نظام میں معیشت وتجارت کی عمارت اخلاقی بنیادوں پر اس طرح قائم نہیں ہوتی جس طرح اسلام نے قائم کی ہے۔ مغربی ماہرین نے یہ بات تسلیم کی ہے۔ ایک بڑے مشہور مغربی ماہر قانون نے لکھا ہے کہ اسلامی شریعت نے اخلاقی قواعد اور اصولوں کو اپنے قانون کے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ قانون پر عمل کرنے والا خود بخود اخلاق پر عمل درآمد کرتا ہے اور اسلام کے اخلاقی اصول کی پاسداری کرنے والا خود بخود اسلام کے قانون پر عمل درآمد کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر وابستہ ہو گئے ہیں۔ مغربی دنیا نے اپنی تاریخ کے ایک دور میں بعض گمراہیوں کی وجہ سے قانون اور اخلاق، قانون اور روحانیات کے رشتے کو توڑ دیا۔ مغربی دنیا نے یہ طے کیا کہ قانون وہ ہوگا جس کا اخلاق اور روحانیات سے تعلق نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قانون کی اصل بنیاد ختم ہو چکی ہے۔ آج غیر اخلاقی اور لااخلاقی تصورات کو قانون کے دائرے میں داخل کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قانون اپنی اہمیت، اپنی افادیت اور اپنی تاثیر کھوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں جو روز بروز لاقانونیت بڑھ رہی ہے، دنیا کی حکومتیں اور بڑے بڑے قائدین جس طرح قوانین کو توڑ رہے ہیں، دنیا کے طے شدہ اصولوں کی جس طرح مٹی پلید کی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اصل وجہ اور اہم وجہ یہ ہے کہ مغربی دنیا نے قانون اور اخلاق کے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ اسلامی شریعت نے پہلے دن سے قانون اور اخلاق، ان دونوں کے رشتے کو اس مضبوطی سے قائم کیا تھا کہ وہ رشتہ آج تک اسی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔
قانون اور اخلاق کی ضرورت مدرسوں اور خانقاہوں میں اتنی نہیں پڑتی۔ خانقاہوں میں بڑی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے۔ مدرسوں میں اور مسجدوں میں ضرورت بہت محدود ہوتی ہے۔ اخلاق اور روحانی اقدار کی ضرورت بازار میں ہوتی ہے۔ اخلاق اور روحانیات کی ضرورت تجارت اور معیشت میں ہوتی ہے۔ جس زمانے میں امام محمد بن الحسن الشیبانی اپنی کتابیں تالیف کر رہے تھے، اس زمانے کے بہت سے محدثین نے زہد پر کتابیں لکھیں۔ امام عبداللہ بن المبارک کی کتاب الزہد اور امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد مشہور ہے۔ متعدد محدثین نے، جن کی تعداد ایک درجن کے قریب ہے، زہد کے موضوع پر کتابیں لکھیں۔ کسی نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ نے زہد پر کتاب نہیں لکھی؟امام محمدنے جواب دیا کہ میں نے کتاب الکسب اور کتاب البیوع لکھ دی ہے۔ خرید وفروخت کے احکام پر، فقہ المعاملات پر میں کتاب لکھ چکا ہوں جو کتاب الزہد کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گی۔ یہ بات امام محمد نے کسی کمزور بنیاد پر نہیں فرمائی۔ امام محمد کے اس قول کی تشریح میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ مدرسے میں اور خانقاہ میں بیٹھ کر اور اپنے گھر کی تاریکی میں بیٹھ کر استغنا وزہد کی بات کرنا آسان ہے، لیکن بازار میں جہاں خرید وفروخت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جہاں دھوکہ دہی کے لیے سو مواقع روزانہ پیدا ہوتے ہیں، کم تولنے کے موقع پیدا ہوتے ہیں، گھٹیا سودا دینے اور بڑھیا سودے کی قیمت لینے کے مواقع روز پیدا ہوتے ہیں اور بازار میں بیسیوں آدمی روز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب ایک شخص اس ناجائز روزی سے بچتا ہے اور جائز اخلاقی، قانونی، دینی تقاضوں کے مطابق تجارت کرتا ہے تو وہ ہر لمحے شیطان کے گلے پر چھری چلاتا ہے۔ یہ جو نفس کا شیطان ہے، اس کے گلے پر چھری چلانا آسان نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر چلائی جا سکتی ہے، خانقاہوں میں چلائی جا سکتی ہے، لیکن جس بازار میں آپ لاکھوں روپے کا کاروبار کر رہے ہوں اور وہ وہاں ایک معمولی غلط بیانی سے لاکھوں روپے کا فائدہ ہونے کا امکان ہو، وہاں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس فائدے سے اپنے کو محروم کرنا یہ دراصل وہ تربیت ہے جو اس روحانی اور اخلاقی اصول سے قائم ہوتی ہے جس پر شریعت نے اپنے احکام کی بنیاد رکھی ہے۔
اللہ کی حکمت بالغہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی اور اللہ تعالیٰ کے لامتناہی علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک بین الاقوامیت کا دور ہوگا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے تمام پیغمبر ، تمام آسمانی مذاہب اور تمام آسمانی کتابیں علاقائی پیغام لے کر آئے۔ کسی نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کوراہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں تو اپنے گاؤں میں آیا ہوں اور اپنے گاؤں کے فلاں حصے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن پاک میں شہادت ہے کہ ایک ایک گاؤں میں تین تین نبی اللہ نے بھیجے۔ ایک گاؤں میں تین نبی ہوں گے تو چند گھروں کے ایک نبی ہوں گے اور دوسرے چند گھروں کے دوسرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھیجا گیا جو بین الاقوامی اور عالمگیر دور تھا اور عالمگیریت کا آغاز ہو رہا تھا۔ آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ بین الاقوامیت کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند عشرے، نصف صدی پہلے شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جدامجد جناب ہاشم بن عبد مناف نے بین الاقوامی تجارتی سفروں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ رحلۃ الشتاء والصیف کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ یہ سفر جناب ہاشم بن عبد مناف کی کوششوں سے شروع ہوا۔ ہاشم نے قیصر روم سے اور شہنشاہ ایران سے اجازت لے کر ان سفروں کے لیے راہداری کے پرمٹ جاری کرائے تھے۔ پھر جناب عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم جناب عباس بن عبد المطلب کا بڑا کاروبار تھا۔
یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پندرہ بیس سال پہلے سے تجارت سے وابستہ تھے اور بطور صادق اور امین کے پورے جزیرۂ عرب میں معروف تھے۔ اسلام کی صف اول کی تمام شخصیات کا تعلق تجارت سے تھا۔ خلفاے اربعہ اور خاص طور سے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی، اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے بڑی تعداد اور اکثریت کا تعلق تجارت سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عبد المطلب، سیدنا زبیر بن العوام سب تجارت کرتے تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی شریعت کے اولین علم بردار تھے جو بین الاقوامی شریعت تھی۔ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں سب سے اہم چیز ہمیشہ سے تجارت اور معاشی معاملات رہے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی روابط کی سب سے بڑی اساس تجارت اور لین دین ہے۔ یہ حضرات پہلے سے بین الاقوامی تجارتی لین دین کر رہے تھے۔ گویا اگر میں یہ عرض کروں تو میں حق بجانب ہوں گا کہ اسلامی شریعت اور تجارت کا پہلے دن سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلامی شریعت اور بین الاقوامی معیشت دونوں پہلے دن سے ایک دوسرے سے وابستہ اور لازم وملزوم ہیں۔ یہ پیغام لے کر وہ شخصیات اٹھیں جو پہلے سے اس میدان میں تھیں، اس لیے کہ اگر کسی ایسی قوم کویہ پیغام دیا گیا ہوتا جو تجارت اور بین الاقوامی معیشت سے ناواقف ہوتی تو اسلام کے ان احکام پر عمل درآمد شاید اتنی آسانی سے نہ ہو سکتا اور اسلام کے وہ احکام جو پہلی صدی ہجری میں مرتب ہونا شروع ہو گئے، وہ شاید نہ ہو سکتے۔
آج اسلام سے پہلے دور کے متعدد قدیم قوانین موجود ہیں اور کتابوں میں لکھے ہوئے دستیاب ہیں۔ یہودیت کا قانون موجود ہے، ہندو لا موجود ہے، رومن لا موجود ہے،لیکن یہ بات میں بلاتامل آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کے کسی بھی نظام اور قانون میں تجارت اور معیشت پر وہ زور نہیں دیا گیا جو اسلامی شریعت نے دیا ہے۔ اسلامی شریعت کے نزول کی تکمیل کے ڈیڑھ سو سال کے اندر اندر ائمہ اسلام نے درجنوں کتابیں ان قوانین پر مرتب فرما دیں۔ امام شافعی کی کتاب الام پورا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس کا جو نیا ایڈیشن چھپا ہے، وہ پندرہ جلدوں میں ہے اور انسائیکلو پیڈیا سے زیادہ ضخیم ہے۔ اسے تن تنہا ایک فقیہ نے بیٹھ کر مرتب کیا اور اس میں تجارت کے احکام اور قوانین کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے بحث کی ہے۔ امام محمد نے ان مسائل پر بحث کی ہے۔ امام محمد سے پہلے ان کے اور امام شافعی کے استاذ امام مالک نے اپنی المدونہ میں، جو چھ جلدوں میں ایک ضخیم کتاب ہے اور بارہا چھپی ہے، تجارت اور معیشت کے تمام جزوی سے جزوی مسائل بیان کیے ہیں۔
تجارت اور معیشت کے احکام بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ان تمام آیات کو جب سامنے رکھا گیا جن میں تجارت اور معیشت کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں تو ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سے ایک ایک فقیہ نے ہزاروں احکام کا استنباط کیا۔ ایک مرتبہ امام شافعی کسی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ جن بزرگ نے عشا کی نماز کی امامت کی، انھوں نے سورۂ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی۔ امام شافعی رات کو آکر سو گئے۔ صبح اٹھے تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت، رات کو نیند آگئی، اچھی طرح سے سوئے؟ امام شافعی نے کہا کہ میں تو ایک منٹ کے لیے نہیں سویا۔ پوچھا جی کیوں؟ امام شافعی نے فرمایا کہ جب تم نے یہ آیت تلاوت کی: وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَۃٍ فَنَظِرَۃٌ إِلَی مَیْْسَرَۃٍ (۲:۲۸۰)۔ قرض دار کا ذکر ہے۔ قرض کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ اگر تمھارا مقروض تنگ دست ہو تو اسے اس وقت تک مہلت دی جائے، اس وقت تک چھوٹ دی جائے جب تک اس کے پاس خوش حالی نہ آجائے، جب تک اس کے ہاتھ نہ کھل جائیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پر غور شروع کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں تو اسلام کا قانون افلاس بیان کیا گیا ہے۔ It is the basis of the law of insolvency in Islam۔ افلاس (Insolvency) کیا ہے؟ وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَۃٍ ۔ آدمی اپنی مالی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ جس آدمی کی مالی ذمہ داریاں اور قرضے اس کے وسائل سے بڑھ جائیں، اس کو قانون میں مفلس کہتے ہیں۔ وہی صورت حال یہاں بیان ہوئی ہے۔ پھر امام شافعی نے فرمایا کہ فوراً ذہن میں یہ آیا کہ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ شریعت نے جو اخلاق معاملات اور تجارت کے بارے میں سکھائے ہیں، وہ قانون افلاس کی بنیاد ہونے چاہییں۔ پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ذہن میں آیا، پھر یہ ذہن میں آیا۔ امام شافعی بیان فرما رہے ہیں اور طلبہ اور شاگرد سن رہے ہیں۔ پھر امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اس آیت سے ایک سو آٹھ مسئلے اخذ کیے ہیں۔ تین حرفی آیت ہے۔ اس تین حرفی آیت سے ایک سو آٹھ مسئلے امام شافعی نے قانون افلاس کے مرتب فرمائے۔
اس ایک مثال سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تجارت اور معیشت کے احکام کی اسلام کے نظام میں کتنی اہمیت ہے۔ فقہاے اسلام نے قانون تجارت اور قانون معیشت یعنی فقہ المعاملات کے جو مسائل منقح کیے، ان میں سے کئی مسائل ایسے ہیں کہ آج بھی مغربی دنیا ان تک نہیں پہنچی۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ یہ جو ذخائر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، اگر تقابل نہ کیا جائے۔ وبضدہا تتبین الاشیاء۔ جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، دوسروں کا نظام اور دوسروں کا قانون کیا بتاتا ہے، اس وقت تک اپنی دولت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور سے، فقہاے اسلام اور مجتہدین کے دور سے ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب شریعت کے احکام پر غور کیا جائے، شریعت کے احکام کو نافذ کیا جائے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ شریعت سے انحراف کے کون کون سے راستے بازار میں موجود ہیں۔ اس سے ایک تو ان راستوں کو بند کرنے کا موقع ملتا ہے ۔ دوسرے شریعت کے احکام کے راستے میں رکاوٹوں کا ادراک ہوتا ہے۔ پھر اس ادراک کی وجہ سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا واقعہ مشہور ہے۔ کئی مورخین نے اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ وہ کسی منصب کے لیے کسی ذمہ دار آدمی کی تلاش میں تھے۔ سیدنا عمر فاروق کا طریقہ تھا کہ کثرت سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے اور کثرت سے مشورہ کرنے کے بعد، غور کے بعد کسی منصب کے لیے افراد کا تقرر کرتے تھے۔ اس دوران میں کسی صحابی نے یا کسی دوست نے کسی صاحب کا نام لیا اور مشورہ دیا کہ آپ ان کو مقرر کر دیں، وہ بہت نیک آدمی ہیں، بہت متقی ہیں۔ بہت ان کی تعریف کی اور تعریف میں کہا کہ کانہ لا یعرف الشر، گویا کہ وہ شر کو جانتے ہی نہیں۔ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ سراپا صلاح وتقویٰ ہیں اور شر کو جانتے ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ ایسا آدمی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اذا یوشک ان یقع فیہ۔ جو شر کو نہیں جانتا، وہ تو شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلے گاکہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ ایسا آدمی چاہیے جو خیر کو بھی جانتا ہو اور شر کو بھی جانتا ہو۔
اس لیے صحابہ کرام کے زمانے سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ائمہ اسلام نے اپنے دور کے تمام رائج الوقت طریقوں اور نظاموں کو جانا پہچانا، ان کا ادراک کیا۔ اس ادراک کے بعد جو مسائل سامنے آئے، ان کو سامنے رکھ کر شریعت کے احکام کومرتب کیا۔ جب سادہ زمانہ تھا، یہودیوں اور کفار مکہ کی گمراہیاں تھیں، عیسائیوں کی گمراہیاں تھیں، تجارت کے معمولی طریقے تھے تو ائمہ مجتہدین نے ان طریقوں سے واقفیت حاصل کی۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جس زمانے میں وہ بیوع اور تجارت کے احکام مرتب فرما رہے تھے تو اس زمانے میں بازار میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اپنے وقت کا ایک حصہ انھوں نے اس کام کے لیے رکھا تھا کہ بازار میں جا کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ تجارت کیسے ہوتی ہے، کاروبار کیسے ہوتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کاروبار کے طریقے کون کون سے ہیں اور کیا ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں وہ شریعت کے احکام کو مرتب کر سکیں۔ پھر جب یونانی علوم وفنون کا دور شروع ہوا تو ائمہ اسلام کی بڑی تعداد نے یونانی علوم وفنون کو حاصل کیا۔ فلسفہ، منطق، ریاضی، اس راستے سے آنے والی گمراہیوں کا سد باب کیا۔ امام غزالی، امام رازی، ابن تیمیہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنھوں نے یونانی گمراہیوں کی اس طرح موثر تردید کی کہ کوئی بڑے سے بڑا یونانی فلسفی اور منطقی اسلام کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں کر سکا، حتیٰ کہ خالص اسلامی علوم کو اس طرح منطقی دلائل سے مرتب اور منظم کر دیا کہ اس زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا منطقی اصول فقہ پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا فلاں مسئلہ یا فلاں اصول غیر منطقی ہے۔ علم کلام کو اس طرح مرتب کیا کہ مسلمانوں کے کسی عقیدے کو کوئی بڑے سے بڑا یونانی غیر عقلی قرار دے نہیں سکا۔
ان مثالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فقہاے اسلام رائج الوقت تجارت اور معیشت، رائج الوقت تصورات، رائج الوقت الحادی نظریات اور رجحانات سے پوری واقفیت حاصل کر کے شریعت کے احکام کو مرتب کر تے تھے۔ فقہاے اسلام نے فقہ المعاملات کے احکام کو مرتب کیا۔ فقہ المعاملات کے احکام کی ترتیب صحابہ کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ تابعین میں بعض حضرات نے فقہ المعاملات میں تخصص کیا۔ امام احمد بن حنبل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بیوع کے احکام سب سے زیادہ مرتب انداز میں سعید بن المسیب کے ہاں ملتے ہیں۔ سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں، سید التابعین کہلاتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طویل عرصہ تک شاگرد رہے ہیں۔ انھوں نے خاص طور پر ان احادیث اور سنت کے ان احکام پر غور وخوض کیا جن کا تعلق بیوع اور تجارات سے تھا۔ ایسا ولی کامل، ایسا محدث جلیل جس کو بہت سے حضرات نے سید التابعین قرار دیا ہے، جس نے سالہاسال صحابہ کرام سے کسب فیض میں گزارے، اس نے تجارت اور معیشت میں آج کل کی اصطلاح کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخصص پیدا کیا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تجارت اور بیوع کی، کاروبار کی اہمیت کو صحابہ اور تابعین نے پورے طور پر پہچانا۔ بہت سے حضرات نے اس میں تخصص پیدا کیا اور اس تخصص کی بنیاد پر ائمہ مجتہدین نے احکام مرتب کیے۔
پھر ان حضرات نے صرف احکام مرتب کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ انھوں نے ان احکام کی بنیادیں دریافت کیں۔ شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ وہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ اس علت کو مختلف صورتوں پر منطبق کرنے کے قواعد کیا ہیں؟ خود مال جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بیع کیا ہے؟ تجارت کیا ہے؟ اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ ان میں سے بہت سے مسائل وہ ہیں کہ مغربی دنیا آج بھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ ہمارے یہاں مدرسے میں فقہ کی جو کتابیں طلبہ پڑھتے ہیں، وہ جب کتاب البیوع شروع کرتے ہیں تو پہلے دو تین صفحے پر مال متقوم اور مال غیر متقوم کی بحث آتی ہے۔ یہ تصور آج مغربی قانون میں اس وقت بھی موجود نہیں ہے کہ مال کی پہلے دن سے دو قسمیں کی جائیں۔ ایک وہ مال ہے جس کی مالیت کو، جس کی ملکیت کو جس کے تصرف اور جس سے استفادے کو قانون جائز تصور کرتا ہے اور ایک قسم وہ ہے جس کو جائز تصور نہیں کرتا۔ آج مغربی دنیا یہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس یہ تصور نہیں ہے۔ متقوم اور غیر متقوم کا تصور آج بھی ہے۔ مثال کے طو رپر پاکستان کے قانون کی رو سے کسی کو ہیروئن رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہیروئن کی خرید بھی ناجائز، فروخت بھی ناجائز۔ وہ شریعت کی رو سے بھی مال غیر متقوم ہے، اس لیے کہ مسکر ہے، لیکن موجودہ قانون میں بھی وہ مال غیر متقوم کہی جا سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنی ملکیت میں توپ نہیں رکھ سکتا، ٹینک نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں ٹینک خریدوں تو وہ خرید بھی ناجائز اور جو بیچے، وہ فروخت بھی ناجائز۔ یہ بات آج مغربی دنیا کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر کسی چیز کی خرید وفروخت پر پابندی لگائی جائے تو کس بنیاد پر لگائی جائے؟ کبھی کہتے ہیں کہ عامۃ الناس کی فلاح میں نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا۔ مختلف اسباب بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی سبب یا کوئی بنیاد ایسی ٹھوس اور جامع نہیں ہے جو ان تمام جزئیات کو محیط ہو جن جزئیات پر پابندی لگانا مقصود ہے۔ فقہاے اسلام نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزاے خیر دے، متقوم اور غیر متقوم، دو اصطلاحات سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔
سود کا مسئلہ آپ کو اکثر پیش آتا ہے۔ تاجروں کو پیش آتا ہے۔ سود میں غلط فہمیوں کی ایک وجہ اصطلاحات کا نہ ہونا بھی ہے۔ فقہاے اسلام نے مال کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ یہ سب فقہ المعاملات کے مباحث ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ایک مال وہ ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جائے۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جس کو خرچ کیا جائے۔ یہ پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں، میں آپ سے لے کر سر پر باندھ لوں اور تقریر کے بعد واپس کردوں تو یہ استعمال ہے۔ آپ کی اس پگڑی کا کچھ نہیں بگڑا۔ جیسی میں نے لی تھی، ویسی ہی واپس کر دی۔ یہ استعمال ہے۔ اس کی عاریت ہوتی ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں عاریت کہتے ہیں۔ ایک مال وہ ہے کہ جب تک میں اس کو خرچ کر کے فنا نہ کر دوں، میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے ایک گلاس پانی مانگوں تو پانی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک میں اس کو پی نہ لوں یا اس کو ہاتھ دھو کر اس کو بہا نہ دوں۔ یہ استہلاک ہے۔ ان دونوں کے احکام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شریعت میں ایک کو عاریت کہتے ہیں، ایک کو قرض کہتے ہیں۔ انگریزی میں دونوں کے لیے borrow کی اصطلاح ہے۔ آپ لائبریری سے کتاب بھی borrow کرتے ہیں اور بینک سے رقم بھی borrow کرتے ہیں۔ اب جو اس فرق سے واقف نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کتاب borrow کر کے اس کا کرایہ دے دوں تو آپ اس کو جائز کہتے ہیں اور بینک سے پیسے borrow کرو ں اور اس کا کرایہ دوں تو آپ ناجائز کہتے ہیں! اس میں فرق کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس کے ہاں یہ تصور نہیں ہے، اصطلاحات نہیں ہیں۔
اس طرح کے بے شمار احکام ہیں جو فقہ المعاملات میں فقہا نے مرتب کیے۔ فقہ المعاملات میں یہ بتایا گیا کہ مال کی تعریف کیا ہے؟ مال کہتے کس کو ہیں؟ جس چیز کو مال کہتے ہیں، اس کی خرید وفروخت کے احکام کیا ہیں؟ پھر مال اور ثمن میں کیا فرق ہے؟ یعنی جس کو آج کل زر (Money) کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی کہ آج کل جو Money کی تعریف کی جاتی ہے، زر کی تعریف کی جاتی ہے، بعینہ یہ تعریف فقہاے اسلام کے ہاں موجود ہے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ زر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ما یقتات بہ، ما یدخر بہ ہو، یعنی جس کو ذخیرہ کیا جا سکے، جس کو محفوظ کیا جا سکے۔ ادخار یعنی Store of value یہ آج کل کی اصطلاح ہے ۔ اس کے لیے امام مالک نے ادخار کی اصطلاح استعمال فرمائی۔ امام مالک سے پہلے روئے زمین پر کسی قانون دان کے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا تھا۔ نہ رومن لا میں ہے، نہ ہندو لا میں ہے نہ ہی یہودی لا میں ہے۔ شریعت میں موجود ہے، امام مالک نے دیا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے ہاں تصور یہ ہے کہ زر وہ چیز ہے جو گنی جا سکے، تولی جا سکے ، ناپی جا سکے۔ یہ تصور بھی آج کل زر کی تعریف میں موجود ہے۔ اس لیے اپنے اس ذخیرے کی قدر کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس ذخیرے سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے تاجر حضرات ان اصطلاحات سے اکثر واقف نہیں ہوتے جو فقہا نے استعمال کی ہیں۔ ہمارے علما اور مفتی حضرات ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے جو جونا مارکیٹ اور صدر میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک درمیانی واسطہ ہو۔ وہ درمیانی واسطہ یہ نوجوان علما ہیں جنھوں نے آج کل کا بزنس ایڈمنسٹریشن بھی سیکھ لیا ہے اور شریعت کے وہ پہلے سے متخصص ہیں۔ یہ حضرات اس نئے دور کے نقیب ہیں، ایک نئے دور کے مناد ہیں جس کی امت مسلمہ منتظر ہے۔ امت مسلمہ سو سال سے اس کی منتظر تھی۔
ابھی ایک دوست نے شیخ الہند کا ذکر فرمایا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے چند مہینے پہلے جامعہ ملیہ کا افتتاح فرمایا تھا۔ جامعہ ملیہ آج ہندوستان کی ایک عام سیکولر یونیورسٹی بن گئی یا بنا دی گئی۔ جامعہ ملیہ کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنایا جائے جو علی گڑھ اور دیوبند کا سنگم ہو، جس میں علی گڑھ کی اور دیوبند کی تمام خصوصیات موجود ہوں۔ شیخ الہند اس کا افتتاح کرنے کے لیے دیوبند سے علی گڑھ تشریف لے گئے تھے۔ علی گڑھ میں افتتاح ہوا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اس کے پہلے امیر یعنی چانسلر مقرر ہوئے تھے اور انھوں نے علامہ اقبال سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کے پہلے وائس چانسلر ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ۱۹۱۹ء، ۱۹۲۰ء میں یہ احساس حضرت شیخ الہند میں موجود تھا جو دار العلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، یہ بات آپ سب کے علم میں ہوگی۔ انھوں نے ۱۹۱۹ء میں اس کا احساس کیا تھا۔ آج ۲۰۱۰ء میں ہم اس احساس کا عملی مظہر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے نوے سال کی تاخیر کر دی ہے۔ اگر یہ نوے سال کی تاخیر نہ ہوتی تو شاید آج ہمارے دوستوں کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملتا کہ ہم دنیا سے پیچھے ہیں، ہم دنیا کے مقلد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ وہ اس تاخیر سے درگزر فرمائے اور اس تاخیر کے نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان برکات ونتائج سے ہمیں مالامال فرمائے جو اس پروگرام سے پیش نظر ہیں۔
اسلام میں تجارت کے احکام فقہ اسلامی کا سب سے بڑا حصہ ہیں۔ فقہ اسلامی کے اگر بڑے بڑے اجزا بیان کیے جائیں تو ایک جز عبادات کا ہے۔ نماز روزہ جو تعلق مع اللہ کے لیے ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ (۵۱:۵۶) اس لیے عبادت الٰہی کے لیے جو احکام ہیں، وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی تجارت کے احکام رکھتے ہیں، بلکہ ترتیب میں وہ سب سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسلمان کی تربیت اور تعلیم کا، مسلمان کی تیاری کا، نئی امت مسلمہ کی نشوونما کا جو سب سے بڑا مرکز اور درس گاہ ہے، وہ ماں کی گود ہے اور گھر ہے، ماں باپ کی سرپرستی ہے۔ نانی اور دادی کی لوریاں ہیں۔ جب تک یہ درس گاہ مسلمانوں میں محفوظ تھی، مسلمان گھر خطرے سے محفوظ تھے۔ آج یہ درس گاہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس درس گاہ کے احکام دیے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات احکام میں ایک تہائی کا تعلق عبادات سے ہے اور ایک تہائی کا تعلق عائلی احکام وقوانین سے ہے۔ اس کے بعد فقہ المعاملات میں فقہاے اسلام نے جتنی تفصیل سے معاملات کو مرتب کیا ہے، اس تفصیل میں، اس وسعت میں، اس گہرائی میں فقہ اسلامی کا کوئی حصہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبادات میں تو کسی تفصیل کی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ عبادات میں نہ کوئی نئی عبادت وضع کی جا سکتی ہے نہ کوئی نئی صورت وضع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے عبادات میں تو جوحدود اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اسی کے اندر رہنا پڑے گا اور اس کے احکام بھی محدود ہوں گے۔ اس کے باوجود فقہاے اسلام نے ہزاروں صفحات پر مشتمل سیکڑوں جلدیں تیار کر دیں ۔ لیکن معاملات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں۔ الاصل فی المعاملات الاباحۃ۔ جو نیا کاروبار یا تجارت آج آپ سوچ لیں کہ آپ فلاں کاروبار کریں گے، اگر اس میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ اس میں ربا نہیں ہے، اس میں قمار نہیں ہے، اس میں غرر نہیں ہے، فلاں فلاں برائیاں نہیں ہیں تو وہ جائز ہے، اس کا نام جو بھی ہو۔ چونکہ اس میں راستہ کھلا ہوا ہے، میدان کھلا ہوا ہے، اس لیے فقہاے اسلام نے ہر دور میں نئی شکلیں مرتب کیں۔ جب کوئی نئی شکل تجارت کی آئی، فقہا نے اس کے احکام مرتب کیے۔
امام محمد اور امام مالک اور امام شافعی کے ہاں بیع الوفاء کا ذکر نہیں ہے۔ بیع الوفاء کے نام سے ایک بیع کا آغاز پانچویں چھٹی صدی میں ہمارے سنٹرل ایشیا میں، سمرقند، بخارا، ماواء النہر میں ہوا تو فقہا نے اس کے احکام مرتب کر دیے۔ سوکرہ یعنی سکیورٹی یا انشورنس کا مسئلہ اٹھارھویں انیسویں صدی میں سامنے آیا تو علامہ ابن عابدین نے سوکرہ کے احکام مرتب کر دیے۔ رد المحتار میں سوکرہ کا باب موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں۔ اس لیے تجارت اور معیشت کے ابواب فقہ اسلامی میں مسلسل وسعت پذیر ہوتے رہے ہیں اور ہر دور میں اس میں نئے اضافے ہوتے رہے ہیں۔ جو بنیادی تصورات تھے، ان کی روشنی میں فقہاے اسلام نے احکام مرتب فرمائے ہیں۔ ایک زمانہ تھاکہ ان قواعد کی تعداد پچیس تیس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اب صورت یہ ہے کہ او آئی سی کی اسلامک فقہ اکیڈمی نے ایک پروگرام بنایا کہ ان قواعد کو مرتب کروایا جائے جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ ان سے پہلے ایک اور سعودی ادارے نے کچھ علما کومقرر کیا کہ معاملات سے متعلق قواعد فقہیہ (Legam Maxims) مدون کریں۔ احکام یعنی Rules of Law نہیں، وہ تو بے شمار ہیں۔ صرف Legam Maxims کو مدون کیا جائے۔ چنانچہ وہ بارہ جلدوں میں مدون ہوئے ہیں۔ انگریزی کی کوئی کتاب جس میں سارے لیگل میکسم جمع ہوں، دو سے زائد جلدوں میں نہیں ہے۔ یہاں صرف معاملات کے لیگل میکسم بارہ جلدوں میں مرتب ہیں، چھپ چکے ہیں۔ اب او آئی سی کی فقہ اکیڈمی نے یہ کام شروع کروایا ہے۔ وہاں کے صدر نے خود مجھے بتایا کہ ہم نے یہ کام شروع کروایا ہے۔ اب تک جو مواد ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سو جلدوں میں یہ کام مرتب ہوگا۔ اس سے آپ فقہ المعاملات کی وسعت کا، گہرائی اور تعمق کا اندازہ کرسکتے ہیں۔ مجھے ابھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ فقہ المعاملات میں دو سال، تین سال یا چار سال میں تخصص کیسے ہوگا۔ میرے خیال میں تو اس میں چار پانچ نسلیں لگانی چاہییں۔ تین نسلیں ہوں جو طے کریں۔ پہلے دادا پڑھے، پھر بیٹا پڑھے، پھر پوتا پڑھے تو جا کے شاید تخصص ہو سکے گا۔ جس قانون کے قواعد فقہیہ، لیگل میکسمز سو جلدوں میں آ رہے ہیں، اندازہ کریں کہ اس میں مہارت کے لیے کتنا وقت درکار ہے، لیکن یہ بیج حضرت مفتی صاحب نے ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنائے، اس درخت سے مزید بیج پیدا کرے، اس بیج سے مزید گل وگلزار پیدا ہوں اور یوں اللہ کرے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو۔
میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا اور شاید اوروں سے زیادہ گفتگو میں نے کر لی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر گفتگو مفید ہوئی تو اس روحانی ماحول کی برکت سے ہوئی۔ غیر مفید ہوئی تو میری کوتاہی اور کم علمی کی وجہ سے ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ سے ایک انٹرویو
مفتی شکیل احمد
شعبان/رمضان ۱۴۲۷ھ بمطابق ستمبر /اکتوبر ۲۰۰۶ء میں جامعۃ الرشید کراچی میں دورۂ اسلامی بنکنگ ہوا۔ اختتامی تقریب سے ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ (۱۹۵۰ء-۲۰۱۰ء) نے معیشت اور اسلامی بنکاری پر تقریباً دو اڑھائی گھنٹے مفصل خطاب فرمایا۔ جامعۃ الرشید سے واپسی پر ڈاکٹر صاحب کو ایئر پورٹ پہنچانے کے لیے راقم الحروف او رمفتی احمد افنان ہمراہ تھے۔ راقم کو ڈاکٹر صاحب سے مختلف وجوہ سے تعلق او رقلبی لگاؤ تھا۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز، بیانات، محاضرات اور مختلف تقریریں سننے کا موقع ملا۔ مختلف سیمیناروں اور کانفرنسوں میں ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی طرح جب ڈاکٹر صاحب کی رہائش ایف سیکس ون اسلام آباد میں تھی تو ہمارے جامعہ محمدیہ (ایف سکس فور) میں پڑوس کی وجہ سے جامعہ کے مختلف پروگراموں میں شرکت فرماتے اور بیانات بھی فرماتے۔ان تعلقات کی بنا پر ڈاکٹر صاحب بہت شفقت فرماتے۔ انھوں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے رسالہ ’’عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سیاست‘‘ پر احقر کی تعلیقات کے شروع میں تقدیم بھی لکھی۔ اس لیے راقم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈاکٹر صاحب سے مختلف سوالات کر کے ان کو قلم بند کر لیا جو قارئین کی دلچسپی او ر استفادہ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ڈاکٹر صاحب سے آخری ملاقات اسی رمضان المبارک ۲۰۱۰ء میں فیڈرل شریعت کورٹ میں ہوئی۔
سوال :ایک چیز مصر میں جائز ہوتی ہے اور پاکستان میں ناجائز، اس کا کیا حل ہے ؟
جواب: معاملات بین الاقوامیت میں جا رہے ہیں تو یکسانیت کے لیے ایک نظام بنانا پڑے گا۔ دنیائے اسلام کا ایک مشترکہ شریعہ بورڈ ہو۔ اسلامی ترقیاتی بنک نے اس کی کوشش کی تھی، لیکن امریکہ سے ڈرتے ہیں ۔
سوال:ڈاکٹر صاحب! تقریر میں آپ نے فرمایا کہ مرابحہ میں جو طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ عمیل کو ہی وکیل بالقبض بنا دیا جاتا ہے، یہ بہت رکیک حیلہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اسلامی بنکاری کا سو فیصد نہیں تو ستانوے فیصد کاروبار مرابحہ پر ہی ہو رہا ہے تو کیا یہ حیلہ آپ کی نظر میں جائز نہیں ہے؟
جواب : یہ حیلہ شرعاً جائز ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والا عقد بھی درست ہے ۔
سوال:اور اس طرح حاصل ہونے والا نفع کیا حلال ہوگا؟
جواب: ہاں !حلال ہوگا ۔
سوال : جب حکومت کسی فیصلے کے ذریعے سے آپ کی کسی محنت کو ختم کر دیتی ہے جس طرح کہ ربا کیس میں ہوا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے تو جنہوں نے براہ راست محنت کی ہے، ان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی؟
جواب:میں ایسے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو یاد کر لیتا ہوں کہ انھوں نے ساڑھے نو سو سال محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کی عمر کو ذکر نہیں فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اس لیے بتائی گئی تاکہ اس سے تسلی حاصل کی جاسکے اور آدمی مایوس نہ ہو اور حوصلہ کم نہ ہو۔ ان کی عمر بیان کرنے سے مقصود یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ بس کام میں لگے رہنا چاہیے۔ تیمور لنگ جب ہار گیا تو کوہستان کے کسی غا ر میں آرام کے لیے پناہ لی۔ ایک چیونٹی سو مرتبہ گری اور پھر چڑھی جس سے وہ آخر کار کامیاب ہو گئی۔ اس سے اس نے سبق حاصل کر کے فوج کو ازسر نو مرتب کیا او رحملہ کر دیا اور کامیاب ہو گیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور کام میں لگے رہنا چاہیے۔
سوال :(از مفتی احمد افنان صاحب)ڈاکٹر صاحب! میں درس قرآن دیتا ہوں، اس کے لیے کس طرح تیاری کروں؟
جواب: تین ،چار تفاسیر کو مطالعہ میں رکھیں اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی تفسیر ماجدی ضرور مطالعہ کریں۔ اس میں جدید شبہات اور مغربی مصنفین کے قرآن پر اشکالات کا ذکر کر کے جواب دیا گیا ہے۔درس قرآن جاری رکھنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں مولانا دلاور صاحب کا پندرہ روزہ درس قرآن ہوتا ہے۔ انھوں نے اسٹیڈیم (غالباً اسٹیڈیم ہی فرمایا) بک کروایا ہوتا ہے۔ اس میں آٹھ نو لاکھ افراد ہوتے ہیں اور عشا سے فجر تک چلتا ہے جس میں تمام قرآن کریم کا خلاصہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔
سوال : ڈاکٹر صاحب! اگر آپ اسلام آباد میں درس قرآن شروع فرمائیں تو بہت لوگ آئیں گے کیونکہ لوگ آپ کے بیان کو بہت پسند کرتے ہیں۔
جواب : (کچھ دیر توقف کیا اور پھر فرمایا:) قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔
سوال : ہمارے مدارس کے جو طلبہ بنکوں اور دیگر عصری اداروں میں چلے جاتے ہیں تو ان کی تربیت میں بھی کمی آجاتی ہے، وہ پہلا سا تدین بھی باقی نہیں رہتا اور اعمال میں بھی سستی ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے ؟
جواب : بنک اور دیگر عصری اداروں کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ اس وضع قطع او رہیئت کو پسند نہیں کرتے تو یہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بالآخر اس وضع قطع اور ہیئت کو ترک کر دیتا ہے۔ تربیت کا سلسلہ تو بہر حال برقرار رہنا چاہیے، لیکن اگر یہ طالب علم اپنے نظریات اور سوچ کے اعتبار سے پختہ ہے تواس میں اس تبدیلی کو بھی میں اتنا برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہزاروں ملحدوں اور بے دینوں سے بہر حال یہ بہتر ہے جن کی سوچ او رفکر ہی بے دینی کی ہے۔ سوچ اور نظریات کی گمراہی بہت بڑی ہے ۔
سید عبد اللہ صاحب عالم تھے اور اردو اد ب کے نقادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت مولا نا احمد علی لاہوری ؒ کے درس قرآن میں شریک ہوتے تھے اور اسلام آباد میں ہوتے تو مولانا غلام اللہ خانؒ صاحب کے درس میں ضرور شریک ہوتے۔ وہ اپنا حال سناتے تھے کہ میں حضرت لاہوریؒ کے درس میں پیچھے بیٹھتا تھا۔ ایک دن افراد کم تھے تو میں قریب بیٹھا اور اپنا چہرہ رومال سے چھپا لیا۔ حضرت لاہوری نے فرمایا: عبد اللہ! قریب ہو جاؤ۔ (یہ سناتے ہوئے ڈاکٹر سید عبد اللہ رو پڑتے تھے)۔ پھر حضرت لاہوری نے فرمایا : ’’سپاہی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک باوردی اور دوسرا بے وردی۔ ضرورت کے وقت وردی اتار دی جاتی ہے۔ بس کام کرنا چاہیے۔ تم کام میں لگے رہو۔ اگر اس طرح کام ہوتا ہے تو اس طرح کام کرتے رہو۔‘‘
سوال: ڈاکٹر صاحب! حافظہ کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ تقریر کے دوران آپ نے پاکستان کی معیشت و بنکاری سے متعلق تیس چالیس سال کی تاریخ بیان کی۔ تاریخیں، دن اور وقت تک بیان کیا جس سے ہمیں بھی تعجب ہو رہا تھا۔
جواب : کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ پہلے میرا حافظہ کافی اچھا تھا، اب شوگر کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ انڈیا سے ایک چورن ملتاہے جسے مہا سرسوتی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے علامہ کبیر، یعنی جو اس کو کھاتا ہے، اس کا حافظہ تیزہو جاتا ہے اور وہ ہندوؤں کا علامہ کبیر اور مہا سرسوتی بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو وہاں سے لانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اب تک نہیں ملا۔
سوال: خمیرہ گاؤ زبان استعمال نہیں کرتے؟
جواب: ہے تو بہت مفید اگر اصلی ملے، مگر اس میں شوگر وغیرہ میٹھا استعمال کیا جاتا ہے اور میں شوگر کے مرض کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا۔ صدر مشرف جب انڈیا گیا تو وہاں ایک حکیم صاحب نے ان کو جوش عقیدت میں پانچ کلو خمیرہ گاؤ زبان کا ڈبہ دیا۔ مشرف صاحب جب اسلام آباد آئے تو کیبنٹ میں وزرا وغیرہ جمع ہوئے اور ان کو دورہ کے حالات بتائے۔ جب اٹھنے لگے تو آخر میں کہا کہ ایک بات میں بھول گیا کہ ایک حکیم صاحب نے پانچ کلو کا ڈبہ دیا تھا۔ اس پر کوئی عربی نام لکھا تھا،پتہ نہیں کیا نام تھا۔ سیکرٹری صاحب نے جیب سے پرچی نکال کر بتایا کہ خمیرہ گاؤ زبان تھا۔ صدر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب (ڈاکٹر غازی صاحب) کو عربی سے تعلق ہے، عربی جانتے ہیں، ان کو دے دو۔ بعد میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس ڈبے کو پھینک دیا گیا ہے۔
سوال: ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے رسالہ ’’عہد نبوی کے اصول سیاست‘‘ پر میں نے کچھ کام کیا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ’’بدرقہ‘‘۔ اس کا معنی اردو لغت میں ’’وہ شخص جو راستے میں مسافر کی حفاظت کرے، قافلہ کا راہنما، نگہبان، محافظ‘‘ ہے۔ کتاب میں کون سا معنی مراد ہے ؟
جواب لغت والے معنی ہی یہاں مراد ہیں۔
سوال : اسی طرح لکھا ہے کہ گوروں کی ’’لنچنگ‘‘ پر اتر آنے والی ننگ انسانیت قوم۔ لنچنگ کے معنی کیا ہیں؟
جواب: یہ لفظ ’’لنچنگ‘‘ (Lunching) نہیں ہے، بلکہ یہ انگریزی لفظ Lynching ہے اور اس کا معنی ہے کسی کو لاٹھیاں مار مار کر ہلاک کرنا۔ گورے دنیا کے جس ملک میں بھی گئے، انھوں نے کالوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور جہاں تک بن پڑا، کالوں کو بلا جواز و بلا قانون لاٹھیاں مار مار کر ہلاک کر دیا، خواہ گورے امریکہ میں گئے خواہ آسٹریلیاوغیرہ میں گئے۔
سوال : آ پ نے بنوری ٹاؤن میں بھی پڑھا ۔ کیا حضرت بنوری ؒ سے بھی کچھ پڑھنے کابھی موقع ملا؟
جواب: ہمارے اصول الشاشی کے استاد مولانا عبد اللہ کاکا خیل صاحب مدینہ یونیورسٹی چلے گئے (جو بعد میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسرہو گئے) تو ان کے جانے کے بعد حضرت بنوری ؒ نے باقی اصول الشاشی پڑھائی۔
سوال: اس کے علاوہ کسی اور بڑے عالم دین سے کچھ پڑھا ہو؟
جواب: حضرت مدنی کے شاگرد حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب ؒ راولپنڈی کے ورکشاپی محلہ میں رہتے تھے۔ ان کا وہاں مسجد و مدرسہ بھی ہے، ان سے حماسہ پڑھی تھی ۔
سوال: آپ نے دورۂ حدیث شریف کہاں سے او ر کس سنہ میں کیا؟
جواب: ۱۹۶۶ء میں تعلیم القرآن راجہ بازار سے کیا۔
سوال: پھرتو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب سے بھی استفادہ کا موقع ملا ہوگا؟
جواب: مولانا اس وقت مہتمم تھے، لیکن ان سے استفادہ کا موقع نہیں مل سکا۔
سوال : تعلیم القرآن میں کن اساتذہ سے استفادہ کیا؟
جواب: مولانا عبد الشکور صاحب ،مولانا عبد الرشید صاحب اور مولانا انور شاہ صاحب سے استفادہ کا موقع ملا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ منتخب پیش لفظ اور تقریظات
ادارہ
’’رد قادیانیت کے زریں اصول‘‘ پر تقریظ
حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی، ان مجاہدین اسلام میں سے ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ دین حق کی سربلندی اور مسلمانان عالم کی ملی وحدت اور یک جہتی کے لیے وقف ہے۔ مولانا چنیوٹی گزشتہ پچاس سے ختم نبوت کے تحفظ کو اپنی زندگی کامشن بنائے ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کے خلاف کھڑی ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہمیشہ مجاہدین اسلا م کی صف اول میں موجود رہے ہیں۔ گزشتہ صدی کے اواخر میں اٹھنے والے فتنہ قادیانیت ومرزائیت کی تردید وتعاقب کو مولانا نے اپنی زندگی کا خاص الخاص مشن قرار دیا ہے۔ اندرون ملک وبیرون ملک اٹھنے والی ہر قادیانی سازش کا انہوں نے فکری، علمی، تعلیمی اور عوامی سطح پر بھرپور مقابلہ کیا۔
اس جہد مسلسل میں اپنے دست وبازو پیدا کرنے اور اس عمل کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مولانا چنیوٹی نے ایک تربیتی پروگرام بھی شرو ع کر رکھا ہے جس کے ذریعے وہ نوجوان علما کو ختم نبوت کی تبلیغ اور قادیانیت کی تردید کے لیے تیار کرتے ہیں۔ زیر نظر کتا ب مولانا چنیوٹی نے ان زیر تربیت نوجوان علما کے لیے مرتب کی ہے جو فتنہ قادیانیت سے ہنوز کما حقہ واقف نہیں ہیں اور اب تربیت کے اس دور میں قدم رکھ رہے ہیں جس سے نکل کر ان کو اس فتنہ سے عہدہ برآ ہونا ہے۔
مجھے امید ہے کہ یہ کتاب نوجوان مبلغین اسلام میں مقبول ہو گی اور ان مقاصد کی تکمیل کرے گی جن کی خاطر یہ مرتب کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مولانا کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دارین میں ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔
Muhammad (pbuh) foretold in the Bible by Name پر پیش لفظ
اسلام اور مسیحیت کے درمیان بحث و گفتگو اتنی ہی پرانی ہے جتناکہ بذات خود اسلام ہے۔ پچھلے چودہ سو سال کے دوران میں اسلام اور مسیحیت کے درمیان بحث و استدلال متعدد نشیب و فراز سے گزرا ہے۔ اسلام، شروع ہی سے اس طویل بحث و استدلال کو ایک پائیدار تعاون اور افہام و تفہیم کی صورت میں ڈھالنے کا خواہاں رہاہے۔ اپنی دعوت کے بالکل ابتدائی مکی دور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے مسیحیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے اور بحال رکھنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وحی کے نزول کے فوراً ہی بعد اسلام کا مسیحی دین سے پہلا سامنا ہوا۔ وحی الٰہی کے اپنے اولین تجربے سے چند ہی گھنٹے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ خدیجہ کے کزن جناب ورقہ بن نوفل سے ملے۔ آپ کے وطن میں ورقہ غالباً اکلوتے دانشور صاحب علم تھے جو مسیحیت کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ نے نہ صرف ا س نئے پیغام کی الہامی بنیاد کا اعتراف کیا بلکہ اس نے اپنے اس جوان مہمان کے سامنے اس کی آئندہ زندگی میں پیش آنے والے حالات و مشکلات کی وسعتوں کی بھی وضاحت کی۔ جو چیز اس بزرگ مسیحی دینی رہنما نے پہچان کر فوری طور پر مان لی، ٹھیک اسی بات کی دیگر آسمانی ادیان کے پیرووں سے بھی توقع ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے مدنی وحی میں یہ دعوت بڑے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں دہرائی ہے۔ اس نے اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ آسمانی مذاہب کے ان مشترکہ مقاصدکی تکمیل کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں جو انسانیت کے لیے برکات الٰہی کی ناقابل شکست زنجیر کا کام دیتے ہیں۔
قرآن کریم کے نزدیک مسلمان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیا و رسل پر ایمان رکھا جائے۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور بائبل میں مذکور دیگر تمام انبیا پر ایمان لائے۔ نبوت کی اس زنجیر کے، جو غیر منقطع طور پر مربوط ہے، تسلسل کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ عقیدہ و ایمان بہت ضروری ہے۔ اس ربط و تسلسل کی اہمیت مزیدواضح کرنے کے لیے ہی سابقہ انبیا اور الہامی کلام نے آخری پیغمبر کی آمد اور آخری و کامل پیغام کے الہام کی پیشین گوئی کی تھی۔ قرآن تو اس حد تک گیاہے کہ اس نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں اور مسیحیوں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اتنی جلدی اور آسانی سے پہچان لیا تھا جتنی جلدی اور آسانی سے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہچان لیتے تھے۔ ایک مشہور قرآنی آیت میں تو یہاں تک آیاہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے پیرووں کو بتا دیا تھا کہ ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے احمد نام کے ایک پیغمبر کی بعثت کی خوشخبری سنا دیں۔
قرآن کے ایسے بیانات کی بنیاد پر مسلم علما سابقہ مذہبی صحائف کے مطالعے میں مصروف رہے۔ سابقہ الہامی کتب پر تحقیق کی حوصلہ افزائی نہ صرف قرآنی آیات میں کی گئی ہے بلکہ ایسی متعدد روایات میں بھی کی گئی ہے جو یہودی اور عیسائی پس منظر رکھنے والے متعدد ایسے صحابہ کرام کی طرف منسوب ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ انہوں نے ایسی چیزوں کی نشان دہی کی ہے جو قرآنی اور دیگر اسلامی بیانات کی تائید کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہودی ومسیحی علما کی اکثریت نہ صرف اپنی الہامی کتب میں ایسی پیشین گوئیوں کے وجود سے انکاری رہی ہے بلکہ یا تو متعلقہ الفاظ و آیات کے تراجم میں تبدیلی کر کے اور یا پھر ان کی مختلف تاویلات کر کے مسلمانوں کے نقطہ نظر کی تردید کرتی رہی ہے۔
کسی متفقہ نقطہ نظر پر پہنچنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ان اکثر آسمانی صحیفوں کے ابتدائی و اصلی متن کی عدم دستیابی ہے جو اب صرف نامعلوم مترجمین کے بالواسطہ اور ثانوی تراجم ہی کے ذریعے سے دستیاب ہیں۔ اس موضوع پر لکھنے والے مسلم علما کاخیال ہے کہ بائبل لٹریچر کے متعلقہ الفاظ و عبارات کا الحاق یہودو نصاریٰ کی طویل تاریخ کے دوران میں واقع ہونے والے مختلف ہنگاموں اور مصائب کے زمانے میں عمل میں آیا ہے۔ ان کے اس خیال کو اس بات سے تقویت ملتی ہے جب ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ بعض الفاظ و اصطلاحات کا بائبل کے مختلف مترجمین نے مختلف انداز میں ترجمہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی علمی و فکری تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلم علما نے اس پر سیرحاصل بحث کی ہے۔ جن علما نے اس علمی کام میں حصہ لیا، ان میں پرانے دور کے طبری، ان حزم، شہرستانی، قرطبی اور رازی جیسے مستند ومسلم علما شامل ہیں اور جدید دور کے مصنفین میں سے رحمت اللہ کیرانوی، دریا بادی اور مودودی شامل ہیں۔ انہوں نے بائبلی لٹریچر کے ایسے الفاظ و آیات کی نشاندہی کی کوشش کی ہے جن میں نبی آخرالزمان کی بعثت کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔
مسیحی مصنفین متعلقہ الفاظ و آیات کی استعارانی مفہوم میں تاویل کرتے ہیں، تاہم علوم بائبل کے مسلم مصنفین کے درمیان متنازعہ الفاظ وعبارات کی تاویل و توضیح کے بارے میں قریب قریب اتفاق ہے۔ بائبل کے عہد نامہ عتیق میں پائی جانے والی ’’غزل الغزلات‘‘ ایسی عبارات میں سے ایک ہے ۔ جناب عبدالستار غوری نے اس عبارت کا گہرائی میں جاکر مطالعہ کیاہے اور پوری کامیابی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کردیں کہ یہ عبارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے اس قدرے طویل عبارت کا مکمل تجزیہ کیاہے اور موثر دلائل ترتیب دیے ہیں۔
موجود ہ کتاب برسوں بلکہ عشروں کے طویل اور صبر آزمامطالعہ و تحقیق کا نتیجہ ہے۔ وہ کافی عرصے سے بائبلی علوم کے ایک سنجیدہ طالب علم رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے مسلم، مسیحی اور یہودی دینی علما کی مشترکہ دلچسپی کے متعدد مضامین اور مطبوعات شائع کی ہیں۔ انہیں بائبل اور اس سے متعلقہ دیگر علوم میں گہری بصیرت حاصل ہے۔ ان کی عبرانی کی واقفیت نے ان کو ایسے مواد تک رسائی میں مدد کی ہے جو انگریزی تراجم میں دستیاب نہیں۔
موجودہ کتاب ان کی علمی زندگی کا ایک کارنامہ ہے۔ طویل مطالعے اور گہری تحقیق پر مبنی یہ کتاب اپنا نقطہ نظر ٹھوس دلائل اور معروضی انداز میں پیش کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے نتائج تحقیق کا غیر مسلم مصنفین کی تحریروں سے موازنہ کر کے موخرالذکر مصنفین کی کمزوریاں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بائبل کی تمام تاویلات کے سلسلے میں قریباً کلیتاً مغربی مآخذ پر اعتماد کیا ہے۔ مستند مسلم مآخذ کا صرف اسی جگہ حوالہ دیاگیا ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلوؤں کا ذکر ہے۔
مجھے امید ہے کہ اس کتاب میں نہ صرف مسلم قارئین دلچسپی لیں گے، بلکہ مسیحی، یہودی اور دوسرے مذہبی گروہوں کے پیروکار بھی اس میں اپنی دلچسپی کا سامان پائیں گے۔ یہ کتاب بڑے بروقت موقع پر سامنے آئی ہے۔ آج مسیحیت اور اسلام کے درمیان تعلقات انتہائی کمزور ہوچکے ہیں۔ مسلم دنیا اور مغرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مناقشہ اور ہنگامہ آرائی کی فضا میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مختلف الہامی مذاہب کے متبعین کے درمیان مفاہمت کی فضا استوار کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی کوشش انسانیت کی عظیم خدمت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جناب غوری کی کتاب اس مقصد کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگی۔ انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگوں کو عموماً اور الہامی مذاہب کے پیرو کاروں کو خصوصاً اس کتاب کا خیرمقدم کرنا چاہیے۔
’’اسلام کا نظام سیاست وحکومت‘‘ پر تقدیم
اسلام کے سیاسی اور دستوری تصورات واحکام اور انتظامی ہدایات پر بیسویں صدی میں بہت وقیع اور قابل ذکر کام ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ بیسویں صدی کے مسلم اہل علم ودانش نے اسلام کے دستوری احکام کو ایک نئی اجتہادی بصیرت کے ساتھ ازسرنو مرتب کیا ہے۔ قدیم اسلامی لٹریچر میں اسلام کے سیاسی تصورات اور دستوری احکام تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور تاریخ وادب کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ خالص سیاسی تصورات اور دستوری احکام پر کتابوں کی تعداد تفسیر، حدیث اور فقہ وکلام کی کتابوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بیسویں صدی کے وسط میں جب بہت سی مسلم ریاستیں پے در پے وجود میں آنی شروع ہوئیں تو جہاں اور بہت سے معاملات ومسائل سامنے آئے، وہاں اسلامی ریاست کی نوعیت، اسلام کے دستوری احکام اور انتظامی ہدایات پر بھی نئے انداز سے غور وخوض کا آغاز ہوا۔ اس عمل میں علما اور فقہا کے ساتھ ساتھ ماہرین دستور وسیاست بھی شامل تھے۔
سالہا سال کی اس مسلسل اجتماعی اور اجتہادی کاوش کے نتیجے میں اسلام کے سیاسی تصورات اور دستوری احکام نہ صرف منقح ہو کر سامنے آ گئے، بلکہ ان کو آج کی دستوری زبان اور رائج الوقت قانونی اصطلاحات میں مرتب بھی کر لیا گیا۔ اسلام کے یہ نومرتب شدہ دستوری احکام دنیاے اسلام کے متعدد ممالک کے قوانین ودساتیر کی تدوین میں، جہاں جس قدر ممکن ہوا، مفید اورموثر بھی ثابت ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی دستور کی تدوین نو اور اسلام کی سیاسی فکر کی تشکیل جدید کا یہ کام فقہ اسلامی کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور نمایاں باب ہے۔ اسلامی دستور کے بعد اب اسلام کی انتظامی ہدایات اور مسلمانوں کے انتظامی تجربات پر بھرپور علمی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ اب دنیاے اسلام کے اہل علم اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔
زیر نظر کتاب افغانستان کے ایک جیدصاحب علم اور بالغ نظر محقق مولانا عبد الباقی حقانی کی فاضلانہ کتاب ’’السیاسۃ والادارۃ الشرعیۃ فی ضوء ارشادات خیر البریۃ صلی اللہ علیہ وسلم‘‘ کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک بہت جامع کتاب ہے۔ فاضل مصنف نے تفسیر وحدیث اور فقہ وکلام کے علاوہ تاریخ، ادب اور تذکرہ کی کتابوں کو کھنگال کر یہ قیمتی مواد جمع کیا ہے جس کے لیے وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کتاب کا اردو ترجمہ مولانا شکیل احمد حقانی اور مولانا سید الامین حقانی نے کیا ہے۔ زبان وبیان میں عربیت کے گہرے اثرات کے باوجود امید ہے کہ ترجمہ عام فہم ثابت ہوگا۔ میں دل کی گہرائیوں سے کتاب کے فاضل مصنف جناب مولانا عبد الباقی حقانی کا شکرگزار ہوں کہ انھوں نے اپنی طویل محنت اور تحقیق کے نتائج کو اتنی جامع ترتیب سے اہل علم کے سامنے پیش کیا۔ میں دست بستہ دعاگو ہوں کہ ان کی یہ کاوش اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور قارئین کے لیے مفید اور نافع ثابت ہو۔
’’خطبات راشدی‘‘ پر پیش لفظ
ایک مشہور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین اور شریعت کا علم ہر دور میں اہل علم کے ایک طبقے کے ذریعے محفوظ رہے گا جو اس علم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان غلط فہمیوں کی تردید بھی کرتے رہیں گے جو انتہا پسندوں اور غلو کاروں کے ذریعے پھیلیں گی، ان بے بنیاد باتوں کی تردید بھی کرتے رہیں گے جو اہل باطل کے ذریعے فروغ پائیں گی اور ان غلط تعبیرات وتصورات کی اصلاح بھی کرتے رہیں گے جو دین کے جاہل اور کم علم عقیدت مند پھیلائیں گے۔ اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مخلص اہل علم کی ایک تعداد ان تینوں ذمہ داریوں کو انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ انھی بابرکت نفوس کی مبارک کوششوں کا ثمرہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی اصل تعلیم کے ساتھ موجود ہیں۔ شریعت الٰہی کا روشن چہرہ آج بھی دنیا کے سامنے منور ہے۔ اکابر اسلام کے تاریخ ساز کارنامے آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہیں۔
اہل علم کے اسی بابرکت قافلے کے ایک قافلہ سالار حضرت مولانا زاہد الراشدی ہمارے دور میںیہی فرائض سہ گانہ انجام دے رہے ہیں۔انھوں نے عرب وعجم اور مشرق ومغرب ہر جگہ اپنی فصیح اللسانی اور رواں قلم کے ذریعے اسلام کا مسلسل دفاع کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ انھوں نے دین اور شریعت کی تعلیمات پر کیے جانے والے اعتراضات کا ہمیشہ موثر اور مثبت جواب دیا ہے۔ باطل پرست طبقات کی طرف سے جب بھی اسلام یا اسلامی تہذیب سے کوئی غلط چیز منسوب کی گئی، مولانا کے موثر اسلوب اور طاقت ور قلم نے اس کی کمزوری کھول کھول کر عیاں کردی۔ دین کے نادان دوستوں اور جاہل عقیدت مندوں کی کمزور تاویلات کے نتیجے میں جب بھی کسی کو دین وشریعت پر اعتراض کا موقع ملا، مولانا زاہد الراشدی نے جرات سے کام لے کر اس موقف کی کمزوری واضح کی۔
مولانا کی یہ فاضلانہ تحریریں پاکستان اور انگلستان کے بیسیوں اخبارات اور رسائل کی فائلوں میں منتشر بلکہ مدفون تھیں۔ اخبارات کی زندگی چند گھنٹوں اور رسائل کی زندگی چند دنوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔اخبارات چند گھنٹوں میں اور رسائل چند دنوں میں ردی کی نذر کر دیے جاتے ہیں۔ عام طو رپر اخبارات ورسائل میں شائع ہونے والی علمی وفکری تحریروں کو محفوظ رکھنے کا کوئی موثر بندوبست نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ مولانا راشدی کے قلم سے نکلے ہوئے یہ جواہر پارے وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ لاہور کے بعض علم دوست حضرات نے ان مضامین کی اہمیت کا احساس کیا اور ان کو یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا کے یہ مقالات ومضامین اور تقاریر وخطبات متعدد جلدوں میں مرتب ہو کر محفوظ ہو جائیں گے اور اہل علم ودانش کے لیے دستیاب ہوں گے۔
مجھے امید ہے کہ مولانا زاہد الراشدی کے یہ وقیع خطبات ومقالات دور جدید میں دعوت وتبلیغ کے نئے اسلوب کو جنم دیں گے اور ان کی مدد سے ملک کے نوجوان علماء کرام تبلیغ دین کے ایک نئے اور منفرد ڈھنگ سے آشنا ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر، علم اور کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تحریروں اور تقریروں کو نتیجہ خیز اور مفید بنائے۔
مختلف اہل علم کے نام ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کے چند منتخب خطوط
ڈاکٹر محمود احمد غازی
بنام: جناب مسعود احمد برکاتی
برادر مکرم ومحترم جناب مسعود احمد برکاتی صاحب دامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا گرامی نامہ (بحوالہ ھ۔ن ۲۰۰۴، مورخہ ۲۷ جون ۲۰۰۴ء) بروقت مل گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بروقت جواب نہ دے سکا۔ امید ہے کہ آپ حسب سابق اس کوتاہی کو بھی معاف فرمائیں گے۔
میرا رشتہ بھی ہمدرد نونہال سے کم وبیش نصف صدی پرانا ہے۔ میں نے بہت بچپن میں، تقریباً چار سال کی عمر سے، ہمدرد نونہال پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے والد مرحوم کی زیر نگرانی تین ساڑھے تین سال کی عمر سے ہی گھر میں نوشت وخواند کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ شروع کے ایک دو سالوں میں نہ تو پورا رسالہ سمجھ میں آتا تھا اور نہ میری یہ بساط تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چند سال کے اندر اندر نہ صرف رسالے کے مضامین سمجھ میں آنے لگے، بلکہ میرا اشتیاق بھی بڑھتا گیا۔ مزید دو ایک سال بعد میں نے تعلیم وتربیت بھی پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جو اشتیاق ہمدرد نونہال کے نئے شمارے کے لیے پورے مہینے رہتا تھا، وہ ابھی تک یاد ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمدرد نونہال کے مضامین میں بچوں کے مزاج اور نفسیات کا خاص لحاظ رکھا جاتا تھا۔
ہمدرد نونہال نے ایسی تربیت کر دی تھی کہ کوئی غیر سنجیدہ یا غیر معیاری تحریر پڑھنے کو کبھی دل نہیں چاہا۔ بچوں کے بہت سے رسالوں میں جنوں اور پریوں، جادو اور ٹوٹکوں، چوری اور ڈاکے جیسے تصورات پر مبنی کہانیاں کثرت سے چھپتی تھیں، لیکن ان میں کبھی بھی میرا دل نہیں لگا۔ ہمدرد نونہال کے جو مضامین میں بہت شوق سے پڑھتا تھا، ان میں مسلمانوں کے کارناموں پر مبنی تاریخی کہانیاں اور واقعات نمایاں ہوتے تھے۔ ہمدرد نونہال اور تعلیم وتربیت کے ساتھ ساتھ مولوی اسماعیل میرٹھی کی درسی کتابیں میرے والد مرحوم نے مجھے حفظ قرآن کے دوران ہی پڑھا دی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد کی زندگی میں اردو زبان کبھی بھی مشکل مضمون معلوم نہ ہوئی۔
ہمدرد نونہال نے میری تعلیم اور تربیت دونوں میں حصہ لیا۔ آج اگر اردو لکھنے اور بولنے کا کوئی سلیقہ حاصل ہے تو اس کا ابتدائی بیج رکھنے میں ہمدرد نونہال ہی شامل ہے۔
میری دعا ہے کہ یہ رسالہ اسی طرح قائم دائم رہے۔
والسلام
محمود احمد غازی
(بشکریہ ’’ہمدرد نونہال‘‘، نومبر ۲۰۰۴ء)
بنام:مولانا زاہد الراشدی
(۱)
برادر مکرم ومحترم جناب مولانا ابو عمار زاہد الراشدی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اپریل ۲۰۰۲ء کا ماہنامہ ’الشریعہ‘ آپ کے دیرینہ لطف وکرم سے موصول ہوا۔ میں روز اول ہی سے اس رسالے کا باقاعدہ قاری ہوں۔ آپ کی تحریروں اور مضامین میں جو اعتدال اور توازن ہوتا ہے، وہ گزشتہ کچھ عرصے سے [ہمارے ہاں] کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تحریریں ملک میں ایک متوازن اور معتدل مذہبی رویے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گی۔
زیر نظر شمارے میں اپنی ایک تحریر دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ حیرت اس لیے کہ اس عنوان سے کوئی مضمون لکھنا یاد نہیں تھا اس لیے ابتداءً اخیال ہوا کہ شاید یا تو غلطی سے میرا نام چھپ گیا ہے یا یہ میرے کسی ہم نام کی تحریر ہے، لیکن جب اصل مضمون پڑھا تو اندازہ ہوا کہ عنوان آپ کا اور معنون اس ناچیز کا۔ غالباً آپ نے میرا وہ لیکچر ملاحظہ فرمایا ہوگا جس سے یہ اقتباس لے کر شائع کیا گیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اور آپ جیسے دوسرے علماء کرام اس پورے لیکچر کو بالاستیعاب مطالعہ فرمائیں۔ آپ کے عطا کردہ اس عنوان سے خیال ہوتا ہے کہ شاید میری کتاب ’خطبات بہاول پور‘ آپ کے لیے دلچسپی کا موضوع ہوگی۔ پتہ نہیں آپ کویہ کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا یا نہیں۔
علامہ اقبالؒ اور مولانا تھانویؒ کے مابین فکری مماثلتوں کے موضوع پر پروفیسر محمد یونس میو کا مضمون اچھا ہے، لیکن بہت مختصر۔ شاید ان کو یہ تجویز کرنا موزوں ہو کہ مولانا رومیؒ کے افکار اور پیغام کے بارے میں علامہ اقبالؒ اور مولانا تھانویؒ کے نظریات وخیالات کا تقابلی مطالعہ نہ صرف دلچسپ ہوگا بلکہ دونوں اکابر کے نقطہ نظر میں حیرت انگیز مماثلتیں بھی اس کے ذریعے سامنے آئیں گی۔ میری طرف سے پروفیسر محمد یونس صاحب کو مبارک باد پیش کر دیں۔
والسلام
نیاز مند
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(الشریعہ، مئی ۲۰۰۲ء)
(۲)
۱۷؍ اگست ۲۰۱۰ء
۶؍رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ
برادر مکرم ومحترم جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔
مجھے معلوم ہوا ہے کہ چند سال قبل آپ نے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ پر کوئی مشاورت منعقد فرمائی تھی جس میں بہت سے اہل علم نے اپنی آراء کا اظہار فرمایا تھا۔ کیا یہ آراء تحریری صورت میں دستیاب ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ مزید برآں غیر اہل حدیث اور غیر سلفی علماء میں کون کون سے حضرات طلاق ثلاثہ کے ایک ہونے کے قائل رہے ہیں؟ ایک درمیانی راستہ حضرت مفتی کفایۃ اللہ صاحب نے اختیار فرمایا تھا۔ کیا دوسرے اہل افتاء کے ہاں بھی یہ رجحان ملتا ہے؟
بہرحال اس موضوع پر جتنا مواد فراہم ہو سکے، وہ مجھے ارسال فرما دیں۔
رمضان المبارک کی نیک ساعتوں میں بھی یاد فرمائیے۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
بنام: مولانا محمد موسیٰ بھٹو
(۱)
مورخہ: ۲۳ ستمبر ۸۹ء
مخدوم ومعظم جناب حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب دامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے، آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ کل آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ معلوم نہیں آپ کو یہ تاثر کیوں ہوا کہ اکیڈمی نے سندھی زبان میں لٹریچر کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ یہ تاثر غالباً گذشتہ چند ماہ کی سست رفتاری سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سست رفتاری بعض انتظامی دقتوں اور دفتری طریقہ کار کی طوالت اور پیچیدگی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ سندھی اسلامی ادبیات کے میدان میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ اس ضمن میں آپ سے ماضی میں جو گفتگوئیں ہوتی رہی ہیں، ان کی روشنی میں حتی المقدور کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استاد محمد قطب کی کتاب ’’اسلام اور جدید ذہن کے شبہات‘‘ کے بارے میں دفتری کارروائی ایک ناگزیر انتظامی مشکل کی وجہ سے ہو گئی تھی جو اب الحمد للہ دور ہو گئی ہے۔ اس ضمن میں جلد ہی آپ کو دفتری مراسلہ مل جائے گا۔
سندھ نیشنل اکیڈمی کے ساتھ تعاون کی تجویز اچھی ہے۔ کیا یہ ممکن ہوگا کہ اس پر آپ تفصیلی تجویز انگریزی میں ٹائپ کرا کر ہمیں بھیج سکیں؟
بائبل، قرآن اور سائنس سندھ کے اہم اہل علم کو بھیجنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایسے افراد کے پتے ہمیں ارسال فرمائیں۔ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو یہ کتاب ارسال کر دیں گے۔
اگر آپ جیسے مخلص اہل علم وفکر ہی کسی مایوسی یا غلط فہمی کا شکار ہوں گے تو ہم جیسوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔
دعاؤں میں یاد فرماتے رہنے کی درخواست ہے۔
والسلام
محمود احمد غازی
(۲)
مورخہ: ۳۰؍ اکتوبر ۸۹ء
برادر مکرم ومحترم جناب حافظ موسیٰ بھٹو صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آپ کا گرامی نامہ مورخہ ۲۵؍ ستمبر مجھے ایک غیر ملکی سفر سے واپسی پر ملا۔ اس کے ہمراہ پتوں کی فہرست بھی مل گئی۔ ہم ان سب اہل علم کو سندھی زبان کی کتابیں بھیج رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تک ’’اسلام اور جدید ذہن کے شبہات‘‘ کی کمپوزنگ مکمل ہو گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جونہی پروف ریڈنگ اور تصحیح مکمل ہو، کتاب ہمیں ارسال کر دیں۔ یہ غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کتاب کے مختلف ابواب الگ الگ کتابچوں کی شکل میں شائع کیے جائیں گے اور ایک ہی پیش لفظ جو میری طرف سے ہے، ہر کتاب میں شامل ہوگا۔
آپ سے مسلسل دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
(۳)
برادر مکرم ومحترم جناب حافظ محمد موسیٰ صاحب بھٹو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آپ کا گرامی نامہ کئی روز ہوئے مل گیا تھا، لیکن میں مختلف مصروفیات کی بنا پر جواب ارسال نہ کر سکا۔
آپ کی مرسلہ کتاب ’’اسلام اور ہمارے مسائل‘‘ بروقت مل گئی تھی اور اس وقت اس سے استفادہ بھی کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں آپ کی تحریروں اور کتابوں کا ایک عرصہ سے مداح ہوں۔ آپ کی ہر تحریر میں نہ صرف صحیح اسلامی خیالات پڑھنے کو ملتے ہیں بلکہ ملک وملت کے مسائل پر آپ کا انداز فکر بڑا پختہ اور حقیقت پسندانہ ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی ان فاضلانہ تحریروں کو وہ قبول عام حاصل نہیں ہوا جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔
آپ کے حسب ارشاد جناب عبد الغنی فاروق کی کتاب ’’ہم کیوں مسلمان ہوئے‘‘ کا کمپوز شدہ مواد ان شاء اللہ ارسال کر دیا جائے گا۔ میں جلد ہی اس بارے میں آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔
والسلام
مخلص
محمود احمد غازی
(۴)
برادر مکرم ومحترم جناب حافظ محمد موسیٰ صاحب بھٹو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔
آپ کا گرامی نامہ مورخہ ۸ ؍ اکتوبر موصول ہوا۔ آپ کے خطوط پڑھ کر ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے خطوط کا سلسلہ منقطع نہ فرمائیے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ کئی ماہ قبل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دور جدید میں دعوت دین، اس کا فلسفہ اور اسلوب ومنہاج کے عنوان سے ایک جامع کتاب اکیڈمی کے لیے مرتب کر دیجیے جس میں آپ کی اب تک کی تحریروں کا خلاصہ آ جائے۔ ہم اس کو اپنے پروگرام میں شائع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کرا سکیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس اکیڈمی کی تمام اردو، انگریزی اور سندھی مطبوعات موجود ہوں گی۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
(۵)
برادر مکرم ومحترم جناب حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آپ کا گرامی نامہ مورخہ ۲۰ جنوری موصول ہوا جس کے ہمراہ آپ نے ماہنامہ بیداری میں شائع شدہ اپنے فاضلانہ مضامین کی ایک فہرست بھی ارسال فرمائی ہے۔ ہم یقیناًان تحریروں سے استفادہ کریں گے اور وقتاً فوقتاً یہ تحریریں آپ سے منگواتے رہیں گے۔
شاید آپ کے علم میں ہو کہ اکیڈمی نے ڈاکٹر رفیع الدین کی دو کتابیں شائع کی تھیں اور ان کو بڑے پیمانے پر اندرون وبیرون ملک علمی حلقوں میں پہنچایا تھا۔ مولانا محمد تقی امینی کی کتابیں خالص فنی قسم کی ہیں اور وہ اکیڈمی کے موضوع سے براہ راست متعلق بھی نہیں ہیں۔ یوں بھی پاکستان میں کئی ادارے ان کی اشاعت کر رہے ہیں۔ کبھی ملاقات ہو تو مخدوم ومعظم جناب ڈاکٹر غلام مصطفی خان دامت برکاتہم کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ ان سے مراسلت کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن مسلسل سفروں کی وجہ سے میں اس کو جاری نہ رکھ سکا۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
(۶)
۹۹۔۱۔۲۰
محترمی ومکرمی جناب حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔
دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی سرگرمیوں سے آپ یقیناًآگاہ ہوں گے۔ اسلام کی دعوت وتبلیغ کے لیے دنیا کی ہر اہم زبان میں کتب کی اشاعت کے علاوہ انگریزی زبان میں دعوتی پرچہ "Dawah Highlights" کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔
اس بات کی بہت عرصہ سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اردو بولنے اور پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے اردو زبان میں ایسا معیاری دعوتی پرچہ شروع کیا جائے جس کے ذریعے وہ نہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ ہو سکیں، بلکہ انھیں موجودہ اور آنے والے دور کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت تحریر اور زور قلم سے نوازا ہے۔ امید ہے دعوۃ اکیڈمی کے مجوزہ ماہنامہ ’’دعوۃ‘‘ کو آپ کی قلمی سرپرستی حاصل ہوگی،مگر اس سے قبل ہمیں آپ کی گراں قدر تجاویز اور مفید مشوروں کی ضرورت ہے کہ اس کے مندرجات میں کیا کچھ شامل ہونا چاہیے۔ تعلیم یافتہ مسلمان بالعموم اور نوجوان وعام پڑھے لکھے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ یہ پرچہ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ بمطابق مارچ ۱۹۹۴ء سے شروع کرنے کا پروگرام ہے۔ اس لیے آپ اپنی تجاویز اور مشوروں سے جلد از جلد نوازیں تاکہ ان کی روشنی میں ’’دعوۃ‘‘ کی اشاعت کو عملی شکل دی جا سکے۔
والسلام
محمود احمد غازی
(۷)
۲۸؍۱۰؍۹۴
برادر مکرم ومحترم جناب حافظ محمد موسیٰ صاحب بھٹودامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آپ کا گرامی نامہ مورخہ ۱۲؍ اکتوبر موصول ہوا تھا۔ اس کے ہمراہ آپ کی مرسلہ کتاب ’’معاشرہ، جدیدیت اور اسلام‘‘ کے نسخے بھی موصول ہوئے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ان شاء اللہ صاحب الرائے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے آپ کے خیالات میں اپنے احساسات کی عکاسی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کوبڑی قربت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دار آخرت کی قربت کا ذریعہ بنائیں۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
(۸)
۱۷؍۶؍۲۰۰۶
برادر گرامی قدر جناب حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
گرامی نامہ موصول ہوا۔ کتابوں کا ہدیہ بھی باصرہ نواز اور بصیرت افزا ہوا۔ جزاکم اللہ
آپ نے جن اہم امور کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کے لیے شکر گزار ہوں۔ اگر آپ ان باخبر مذہبی شخصیات سے کہہ سکیں کہ وہ کبھی مجھ سے مل لیں تو میں ان کے تحفظات کے بارہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ ان شاء اللہ گفتگو کے بعد ان کے خدشات دور ہو جائیں گے۔
دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
(۹)
اسلام آباد
۱؍۱۱؍۱۹۹۴ء
برادر مکرم ومحترم جناب حافظ محمد موسیٰ صاحب بھٹو دامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آپ کا گرامی نامہ مورخہ ۱۲؍ اکتوبر ۱۹۹۴ء بروقت مل گیا تھا اور اس کے ہمراہ آپ کی نئی تصنیف: معاشرہ، جدیدیت اور اسلام کے بیس نسخے بھی مل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں روانی، وسائل میں فراوانی اور ذوق وشوق میں طغیانی بیش از بیش فرمائیں۔ آپ سے وہ بہت کام لے رہے ہیں۔ ان شاء اللہ ان کاموں کے واضح نتائج بھی جلد سامنے آئیں گے۔
میں اب دعوہ اکیڈمی کی ذمہ داریوں سے الگ ہو گیا ہوں اور یونیورسٹی کے دوسرے شعبہ میں آ گیا ہوں۔ اکیڈمی کی سربراہی اب ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے سپرد کی گئی ہے۔ وہی ا س کے بانی اور موسس بھی تھے اور گزشتہ چار سال سے ملائشیا میں تدریسی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ دعا فرمائیے کہ اکیڈمی کے اچھے کام ان کی سربراہی اور نگرانی میں اور اچھے ہوں اور جاری رہیں اور ان کے نااہل پیشرو کی کمزوریاں ان کے ہاتھوں دور ہوں۔
ایک عرصہ سے مخدوم ومعظم جناب ڈاکٹر غلام مصطفی خان صاحب کی خیریت معلوم نہیں ہوئی۔ نیاز حاصل ہو تو سلام عرض فرما دیں۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
بنام: ڈاکٹر سید عزیز الرحمن
(۱)
اسلام آباد ۱؍۳؍۱۹۹۹ء
برادرمکرم ومحترم جناب مولانا سید عزیرالرحمان صاحب دامت برکاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کے دونوں گرامی نامے بروقت موصول ہو گئے تھے (۱) لیکن میں قبل از یں جواب ارسال نہ کر سکا جس کے لیے دل سے معذرت خواہ ہوں۔ حضرت مولانا سید فضل الرحمان صاحب از حد مبارک بادکے مستحق ہیں کہ شش ماہی تحقیقی مجلہ السیرۃ کا اجراء فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں اور وسائل سے مالا مال فرمائیں۔ رسالہ کا نکالنا تو آسان، لیکن اس کا جاری رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلا شمارہ اس وقت شائع کیا جائے جب آئندہ تین چار تیار شمارے موجود ہوں۔ مزید برآں علمی اور تحقیقی رسائل معاشی طور پر viable نہیں ہوتے۔ اکثر وبیشتر ان پر خرچ ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان کی فروخت سے یافت ہوناشاذ ونادر صورتوں میں ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ لہٰذا آئندہ تین چار شماروں کے مواد کے ساتھ ساتھ ان شماروں کے اخراجات کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ علمی اور تحقیقی رسائل میں اشتہارات سے بھی زیادہ آمدنی نہیں ہو پاتی، لہٰذا اس مد سے بھی کسی خاص مدد کی امید نہ رکھنی چاہیے۔
رسالہ کو محدود معنوں میں سیرت کے موضوعات تک محدود نہ رکھیے، بلکہ اگر اس کا دائرہ کار معارف نبوت یا علوم نبوت یا پیغام سیرت رکھا جائے توموزوں ہو۔
محترم جناب سید سعید احمد شاہ صاحب علیل تھے، اب ٹھیک ہیں اور ہسپتال سے گھر آ گئے ہیں۔ (۲)
والسلام
نباز مند وطالب دعا
محمود احمد غازی
(۲)
محترم جناب سید عزیرالرحمان صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا گرامی نامہ مورخہ ۳۱؍ جنوری ۲۰۰۱ء بنام ڈاکٹر محمو د احمدغازی صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور،زکوٰۃ وعشر موصول ہوا۔
ڈاکٹر غازی صاحب نے آپ کے مراسلے اورالسیرۃ انٹرنیشنل کا شکریہ ادا فرمایا ہے۔ (۳) آپ نے اپنے مکتوب میں جن دیگرامور کی جانب ڈاکٹر صاحب کی توجہ مبذول کروائی ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے مجاز افسروں کو مناسب غوروخوض اور ضروری کاروائی کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ (۴) اس سلسلے میں ہونے والی پیشرفت سے آپ کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔
والسلام
سید قمر مصطفی شاہ
پرنسپل سٹاف آفیسر برائے وزیر محترم
(۳)
اسلام آباد ، یکم اگست ۲۰۰۱ء
برادر مکرم و محترم جناب سید عزیرالرحمان صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کے متعدد گرامی نامے اور ششماہی عالمی السیرۃ کے شمارے موصول ہوئے ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے مفید مشوروں اور تجاویز سے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔
سیرت کانفرنس کی بابت آپ نے جو امور تحریر فرمائے تھے، ان پر غور وخوض کر کے اس سال سیرت کانفرنس کے انتظامات بہتر بنائے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حسب سابق اپنے مفیدمشوروں سے نوازتے رہیں گے۔
والسلام
نیاز مند
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(۴)
اسلام آباد، ۹؍جولائی ۲۰۰۲ء
محترم جناب سید عزیرالرحمان صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کاوقیع رسالہ عالمی السیرۃ باقاعدگی سے ملتا رہتا ہے۔ اس کے عالمانہ مضامین اور تحقیقی مقالات نے اس رسالے کو بہت جلد ایک نمایاں مقام عطا کر دیا ہے۔ اس سے خوشی ہوئی کہ آپ پروفیسر سید محمد سلیمؒ کے افکار وخیالات پر رسالہ تعمیر افکارکے تعاون سے ایک خصوصی اشاعت کااہتمام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تعمیر افکار کا یہ خصوصی شمارہ ایک اہم تاریخی دستاویز ہو گا۔ پروفیسر سیدمحمد سلیم مرحوم کا علمی مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ ان پر ایک نہیں، بہت سے رسائل کے خصوصی شمارے شائع کیے جائیں۔ انہوں نے علم وتحقیق کے مختلف میدانوں میں جتنا وقیع کام کیا ہے، اس پر دیر تک اہل علم تحقیق کرتے رہیں گے۔
میں بڑے اشتیاق اور شدت سے رسالہ تعمیر افکار کے خصوصی شمارے کا منتظر ہوں۔
والسلام
نیاز مند
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(۵)
تاریخ: ۱؍۸؍۲۰۰۶
برادر مکرم جناب مولانا حافظ سید عزیر الرحمان صاحب زیدت معالیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
گرامی نامہ، کتابیں اورمقالہ (۵) سب ہدایا ایک ساتھ موصول ہوئے۔ جزاکم اللہ۔
مقالہ الحمدللہ بہت عالمانہ ہے۔ جلد سے جلد اشاعت کا اہتمام فرمائیے۔ عجیب توارد ہے کہ یہی موضوعات میرے ذہن میں بھی ہیں جو آخری تین خطبات میں زیر بحث آئیں گے۔ (۶) توارد پر ایک لطیفہ وقت ملاقات سناؤں گا۔
محترم ڈاکٹر کشفی صاحب کا بھی دلی شکریہ ادا کر دیں۔ ان سے ملاقات کی لذت ابھی تازہ ہے۔ (۷)
آج ان شاء اللہ خطبہ ہشتم ہے،ہفتہ تک بارہ خطبے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی کسی خطبہ کی نقل تیار ہوئی، آپ کو ارسال کر دوں گا۔ (۸)
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
(۶)
دوحہ: قطر
۱۶؍ اکتوبر ۲۰۰۹ء
جمعۃالمبارک
برادر مکرم جناب ڈاکٹر سید عزیر الرحمان صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ٓامید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ عرصہ دراز سے، غالباً اگست کے اوائل کی ملاقات کے بعد سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، خدا کرے خیر ہی ہو۔
اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اسلامی بنکاری والی تقریر پر نظر ثانی ہو گئی ہے۔ (۹) لیکن اب بھی مزید نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک بار کھلا کھلا کمپوز کرا کے مجھے واپس بھیج دیں۔ ان شا ء اللہ اس بار تاخیر نہ ہوگی۔
پروفیسرعبدالجبار شاکر صاحب کے اچانک رخصت ہوجانے سے بہت صدمہ ہوا ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت مخلص اور متدین انسان تھے۔ ان کے اہل خانہ میں سے کسی سے رابطہ ہو تو میری طرف سے تعزیت بھی کر دیں اور ان کا نمبر وغیرہ بھیج دیں تاکہ میں براہ راست بھی رابطہ کر سکوں۔
ان کا ذاتی کتب خانہ بہت عالی شان اور وسیع تھا۔ کتابوں کا واقعی بہت عالمانہ اور اچھا ذوق رکھتے تھے۔ اللہ کرے کہ کتب خانہ سلامت اور یکجا رہے۔ خالد اسحاق صاحب مرحوم کے کتب خانہ کی طرح تتر بتر نہ ہو۔
’’اسلام اور مغرب‘‘ والے مقالات کا کیا ہوا؟ (۱۰) یہ صرف استفسار ہے، اصرار نہیں ۔ دعوہ اکیڈمی (کراچی مرکز) کی سرگرمیاں کیسی چل رہی ہیں؟ والد صاحب سے سلام عرض کر دیں۔
والسلام
محمود احمد غازی
(۷)
تاریخ: ۱۶؍ستمبر ۲۰۱۰
برادر مکرم جناب ڈاکٹر سید عزیر الرحمان صاحب زیدت معالیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔
کل کی زحمت دہی پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ بلاوجہ گرمی میں آپ کو (محض اپنے ذاتی کام کے لیے) پچاس میل سے سفر کی زحمت دی۔ ( ۱۱) براہ کرم درگزر فرمائیے گا۔ کتابیں (تاریخ الحرکۃ المجددیۃ) کے نسخے مل گئے، جزاکم اللہ۔ قرآن نمبر کے لیے منتخب کردہ خطبہ پر سرسری نظر ثانی کر دی ہے۔ (۱۲)
والسلام نیاز مند
محمود احمد غازی
(۸)
۱۹ ؍اکتوبر۲۰۰۸
۲۰شوال المکرم ۱۴۲۹ھ
دوحہ۔قطر
برادرم مکرم و محترم جناب مولانا ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمن صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعدے کرنے میں بہت سخی واقع ہوا ہوں، نبھانے کے معاملہ میں صفر ہوں۔ اس شکل سے نکلنے کا واحد راستہ صبر ہی ہے،لہٰذا صبر سے کام لیجیے۔
بنکاری والی تقریر میں معاملہ صفر سے ذرا آگے بڑھا ہے۔ثبوت کے طور پر یہ آدھی تقریر ارسال خدمت ہے۔ بقیہ بھی جلدہی پیش کر دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ تصحیحات کے بعد تین گنا space پر ٹائپ کرائیے گا، اس لیے کہ ایک بار مزید اصلاح ہوگی تو یہ بے سروپا گفت گو قابل اشاعت ہو سکے گی۔
بقیہ وعدوں کے ایفا کی رفتار کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہو گا۔
والسلام
نیاز مند
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(۹)
۲۵ اکتوبر۲۰۰۸
۲۶شوال المکرم ۱۴۲۹ھ
برادرم مکرم و محترم جناب مولانا ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمن صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے!
آج اپنے کاغذات میں یہ مقالہ نظر پڑا۔ یہ میں نے مکہ مکرمہ کی کانفرنس (جون ۲۰۰۸) میں پڑھا تھا۔ یاد آیا کہ آپ نے اس کی نقل بھیجنے کو کہا تھا۔ تاخیر ہی سے سہی، مگر تعمیل ارشاد کی سعادت ہوگئی۔
والسلام
نیاز مند
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(۱۰)
برادرم مکرم و محترم جناب مولانا ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمن صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
مزاج گرامی!
اسلامی بنکاری والی تقریر کا آخری حصہ ارسال خدمت ہے۔ اس میں کم از کم دو بار مزید اصلاح و ترمیم کرنا ہوگی، جب جا کر یہ قابل طباعت ہو سکے گی۔ دوبارہ جب بھیجیں تو تین گنا space پر ٹائپ کرائیے گا تاکہ اصلاح میں آسانی رہے۔
والسلام
نیاز مند
ڈاکٹر محمود احمد غازی
۲۳ اکتوبر ۲۰۰۸
(معاف کیجیے گا کہ علم اور ہمت کے ساتھ ساتھ قلم نے بھی جواب دے دیا ہے۔)
حواشی (از ڈاکٹر سید عزیز الرحمن)
۱۔ ۱۹۹۹ء میں شش ماہی السیرۃ کے اجرا کے موقع پر اہل علم کو خطوط لکھے گئے تھے۔ بعض حضرات کو یاد دہانی کے لیے اس کی نقل مکرر روانہ کی گئی تھی۔ یہ خط اس کے جواب ہی موصول ہو اتھا۔
۲۔ سید سعید احمد شاہ صاحب ادارۂ تحقیقات اسلامی میں ناظم مطبوعات تھے ۔ یونیورسٹی کی نہایت قابل احترام بزرگ شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ دادا جان مولانا سید زوار حسین شاہ ؒ سے بیعت تھے۔ اسی نسبت سے ڈاکٹر صاحب نے خط میں ان کا تذکرہ کیا تھے۔
۳۔ ان دنوں السیرۃ کا چوتھا شمارہ شائع ہوا تھا جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ارسال کیا گیا تھا۔
۴۔ حج کے معاملات اور وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام ہر سال منعقد ہونے والی سیرت کانفرنس کے بعض امور کی جانب ڈاکٹر صاحب کی توجہ دلائی تھی۔ اس کے جواب میں ان کے دفتر سے یہ خط موصول ہوا۔
۵۔ راقم نے ایک تقریب میں سیرت نگاری پر ایک گفتگو کی تھی جو اس وقت شائع نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریک پریہ مضمون شائع آنے کی ہمت ہوئی اور یہ مضمون ’’مطالعہ سیرت کی وسعت ، براعظم پاک وہند‘‘ کے عنوان سے شش ماہی السیرۃ کے شمارہ نمبر ۱۸ میں شائع ہوا ہے۔
۶۔ ان محاضرات کے عنوانات ہیں: مطالعہ سیرت پاک وہند میں۔ مطالعہ سیرت دور جدید میں۔ مطالعہ سیرت مستقبل کی ممکنہ جہتیں۔ یہ مجموعہ محاضرات سیرت کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔
۷۔ ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں کراچی تشریف لائے تو ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشفی ؒ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پھر راقم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کشفی صاحب کے ہاں حاضر ہوا تھا۔ اس کا ذکر ہے۔
۸۔ ان دنوں ادارہ تحقیقات اسلامی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب کے محاضرات سیرت جاری تھے، اس کا ذکر ہے۔
۹۔ تقریر جامعۃ الرشید کراچی کی گئی تھی او ر اپنے موضوع پر نہایت مفصل تقریرتھی۔ یہ پہلے دو اقساط میں ماہنامہ تعمیر افکار کراچی کے جنوری ، فروری ۲۰۱۰ء کے شماروں میں شائع ہوئی تھی۔ بعد میں اسے کتابی شکل میں ’’اسلامی بنکاری ۔ایک تعارف‘‘ کے عنوان سے دارالعلم والتحقیق کی طرف سے شائع کیا گیا۔ (صفحات ۱۱۱۔ مار چ ۲۰۱۰ء)
۱۰۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ چھے حاضرات راقم نے مرتب کیے تھے۔ ان کی اشاعت میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ یہ مجموعہ ’’ اسلام اور مغرب تعلقات‘‘ کے عنوان سے دسمبر ۲۰۰۹ء میں دارالعلم والتحقیق سے شائع ہوا۔ (صفحات ۲۲۱)
۱۱۔ یہ خط راقم کے نام ڈاکٹر صاحب کا آخری خط ثابت ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کی عربی کتاب تاریخ الحرکۃ المجددیۃ دارالکتب العلمیۃ بیروت سے ۲۰۰۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے کچھ نسخے ذاتی طور پر خریدنے کا عندیہ ظاہر کیا تو راقم نے وہ نسخے حاصل کرکے ارسال کر دیے تھے۔ ان کی رقم کی ادائیگی کے لیے ڈاکٹر صاحب مصر تھے۔ راقم نے عرض کیا کہ عندالملاقات وصول کر لوں گا، اس کی فکر نہ فرمائیں۔ ۱۴؍ ستمبر کو ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ بینک کے شریعہ ایڈوائزی بورڈ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ یہ میٹنگ ۱۵؍ ستمبر کو تھی۔ اسی روز وہاں سے فراغت کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ائیرپورٹ روانگی تھی۔ ان کاحکم ہو ا کہ میں اسٹیٹ بنک میں ہی مل لوں۔ اس لیے وہاں جانا ہوں جس کا خط میں ذکر ہے اور راقم کو رقم کی ادائیگی وہ ذاتی کام تھاجس پر ڈاکٹر صاحب معذرت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر!
۱۲۔ڈاکٹر صاحب کا یہ خطبہ ان کی سلسلہ محاضرات کی آخری کتاب ’’محاضرات معیشت وتجارت‘‘ کا ابتدائی خطبہ ہے جس میں معیشت کی قرآنی ہدایات پر گفتگو کی گئی ہے۔ راقم نے ان میں چند حوالوں کا اضافہ کر کے اسی ملاقات ہی میں مضمون ڈاکٹر صاحب کو پیش کیا تھا تاکہ وہ ایک نظر اسے ملاحظہ فرما لیں۔ یہ خطبہ ان شاء اللہ ماہ نامہ تعمیر افکار کے قرآن نمبر میں شائع ہو گا۔
بنام: حافظ صفوان محمد چوہان
مورخہ ۱۴؍ ۴؍ ۲۰۰۵ء
بردر مکرم ومحترم جناب حافظ صفوان محمد چوہان زیدت معالیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا گرامی نامہ چند روز قبل ملا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بروقت جواب ارسال نہ کرسکا۔ اس سے خوشی ہوئی کہ آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسے شعبوں سے وابستہ رہتے ہوئے (جو خالص فنی اور سائنسی نوعیت کے ہیں) دینی اور ملی موضوعات سے بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی اور ملی کاموں میں تعمیری حصہ لینے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔
میری ناچیز گفتگو کو آپ نے پسند فرمایا۔ ممنون ہوں۔ یہ زبانی اور فی البدیہ گفتگو تھی جس میں مرتب خیالات اور پختہ نتائج پیش کرنا آسان نہیں (کم از کم میرے لیے) ۔ اب خیال ہو رہا ہے کہ اس transcription کو سامنے رکھ کر اس میں تفصیلی نظرثانی اور حک واضافہ کروں تاکہ جو با تیں وہاں زیادہ تفصیل سے عرض نہیں کی جا سکیں، وہ تفصیل سے سامنے آ جائیں۔
’’الشریعہ‘‘ کے بارہ میں میرے تاثرات بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں۔ اس کا سارا کریڈٹ مولانا زاہدالراشدی صاحب کو جاتا ہے۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
بنام: ڈاکٹر سید شاہد حسن رضوی
مکرمی جناب ڈاکٹر سید شاہد حسن رضوی صاحب
السلام علیکم
آپ کا ارسال کردہ سہ ماہی الزبیر موصول ہوا۔ اس سے قبل بھی ایک دو شمارے پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ ایک انتہائی خوشگوار حیرت اس سے ہوئی کہ بہاول پور کا یہ رسالہ علم و ادب کے بڑے بڑے مراکز سے نکلنے والے بھاری بھرکم رسالوں سے کم نہیں۔ زیر نظر شمارے میں مشفق خواجہ مرحوم کے نام جو گوشہ مختص کیا گیا ہے، وہ بھی خاصے کی چیز ہے۔
میری ناچیز تحریریں عموماً دینی اور فقہی موضوعات پر مشتمل ہوتی ہیں جو شاید آپ کے رسالے کے لیے غیر موزوں ہوں۔ البتہ کبھی کبھی عربی یا فارسی میں کچھ اشعار نظم ہوجاتے ہیں جن کی حیثیت معنوی اعتبار سے صرف ذاتی احساسات اور لفظی اعتبار سے محض تک بندی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یوں یہ بھی آپ کے معیار سے فروتر سمجھی جائے گی۔
البتہ ایک گزارش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ یہ کہ عموماً اہل دین اور اہل تقویٰ کی ادبی کاوشوں کو اہل ادب کی بارگاہ میں زیادہ پذیرائی نہیں ملتی۔ اس دربار میں وہی لوگ باریاب ہوسکتے ہیں جو اخلاقیات اور روحانیات کے لباس سے یا تو عملاً عاری ہوں یا کم از کم نظری طور پر عاری ہونے کے دعوے دار ہوں۔ اگر سہ ماہی الزبیر اس رجحان کی اصلاح کی کوشش کرے تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی۔ مثال کے طور پر اردو کے مشہور شاعر محسن کاکوروی کا کلام کسی بھی اعتبار سے اردو کے بڑے بڑے اساتذہ کے کلام سے کم نہیں، لیکن ہماری ادبی تاریخیں اور تنقیدی تحریریں ان کے ذکر سے خالی ملتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے لوگ جن کی شعری کاوشیں بہت پست معیار رکھتی ہیں، ادیبوں اور نقادوں کے ہاں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں۔
(بشکریہ سہ ماہی الزبیر، بہاولپور ۔ شمارہ ۳، ۲۰۰۶ء؛ ص ۲۸۹)
[اس خط کے جواب میں بندہ نے اپنے والد صاحب کا مضمون: ’’محسن کاکوروی کی نعتیہ شاعری‘‘ الزبیر میں بھجوایا جو شمارہ ۴، ۲۰۰۶ء میں چھپا۔ اس پر غازی صاحب کا خط شاید شمارہ۔۱، ۲۰۰۷ء میں چھپا ہوگا، لیکن یہ رسالہ مجھے فی الوقت نہیں مل رہا۔ (حافظ صفوان محمد)]
بنام:شہزاد چنا صاحب
(۱)
مور خہ ۴؍ جنوری ۲۰۰۶ء
برادرم جناب شہزاد چنا صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ اس کے ہمراہ’’ قرآن: ایک تعارف‘‘ کے سندھی ترجمے کی پہلی قسط بھی موصول ہوئی۔ جزاکم اللہ ۔
سندھی زبان میں لٹریچر کی تیاری کے لیے بہتر مشورہ اور رہنمائی مولانا امیر الدین مہر صاحب ہی دے سکتے ہیں۔
والسلام
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(۲)
مورخہ ۲۲؍ مارچ ۲۰۰۶ء
برادر مکرم ومحترم جناب شہزاد چنا صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا گرامی نامہ مورخہ ۱۳؍ مارچ ۲۰۰۶ء موصول ہوا۔’’ الفاروق‘‘ اور ’’وینجھار ‘‘ کے تازہ شمارے بھی مل گئے ۔ اس سے خوشی ہوئی کہ ’’ الفاروق‘‘ کے ایڈیٹر مولانا محمدحسین شاہ نے بھی اس کاوش کو پسند کیا ہے۔ عربی لفظ ’’نجماً نجماً‘‘ کا ترجمہ ’’تھوڑا تھوڑا‘‘ ٹھیک ہے۔ مفسرین کرام نے آیت قرآنی کے لیے ’’ تھوڑا تھوڑا‘‘ کا لفظ خلاف ادب سمجھا، اس لیے اس کے بجائے ’’نجماً نجماً‘‘ کی اصطلاح استعمال کی جن کے لغوی معنی ’’ستارہ ستارہ‘‘ کے ہیں۔ گویا قرآن مجید رشد وہدایت کی ایک کہکشاں ہے جس کے ستارے ایک ایک کر کے اتر رہے تھے اور کہکشاں کی تکمیل کر رہے تھے۔ اس لفظ میں جو معنویت اور خوبصورتی ہے، وہ کسی اور لفظ میں ممکن نہیں۔ جس صاحب ذوق اور صاحب دل مفسر نے پہلی بار یہ اصطلاح استعمال کی، اس کے ذوق کو سلام کرنا چاہیے۔
والسلام
ڈاکٹر محمود احمد غازی
(۳)
مورخہ ۳۱؍ جنوری ۲۰۰۶ء
برادر مکرم ومحترم جناب شہزاد چنا صاحب
السلام علیکم ورحمۃا للہ وبرکاتہ
گرامی نامہ مورخہ ۲۵؍ جنوری ۲۰۰۶ء موصول ہوا۔ ’ ’قرآن پاک:ایک تعارف ‘‘کے سندھی ترجمہ کی دوسری قسط بھی موصول ہوئی۔ اس سے خوشی ہوئی کہ مولانا امیر الدین مہر صاحب اس ترجمہ پر نظر ثانی فرما رہے ہیں۔ اگر مولانا کی رائے میں اس کتابچے کے سندھی ترجمہ کی اشاعت مفید ہوتو اس کے مکمل ہونے پر ایک کتابچے کی شکل میں شائع کرنے پر غور کریں اور مشورہ دیں۔
اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے۔ اب دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا مرحلہ درپیش ہے۔ چونکہ مولانا امیر الدین مہر صاحب اس کو ساتھ ساتھ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اس لیے ان سے درخواست کریں کہ کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں جو ترامیم، اضافے اور اصلاحات ضروری ہوں، ان کی نشان دہی فرما دیں۔
میر ی طرف سے مرکز کے تمام احباب اور مولانا امیر الدین مہر صاحب کو سلام عرض کر دیں۔
والسلام
محمود احمد غازی
بنام: محمد عمار خان ناصر
(۱)
06/8/03
برادر مکرم ومحترم جناب مولانا عمار ناصر صاحب، مدیر الشریعہ گوجرانوالہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے کہ آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ مسجد اقصیٰ کی شرعی حیثیت کے بارے میں آپ کا فاضلانہ مقالہ بروقت مل گیا تھا۔ میرے لیے اس کے مندرجات کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا تو دشوار ہے، اس لیے کہ میں نے مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں جو کچھ مطالعہ کیا تھا، اس پر خاصی مدت گزر چکی ہے۔ اب ازسرنو مطالعہ تازہ کرنے کے لیے کتابوں کی ورق گردانی ناگزیر ہے جس کی سردست فرصت نہیں۔ تاہم اگر آپ چاہیں تو علامہ ابن قیم الجوزیہ کی کتاب احکام اہل الذمہ کا مطالعہ فرمائیں جس میں انہوں نے شروط عمریہ پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ میری ناچیز رائے میں شروط عمریہ ہی اس معاملہ میں مسلمانوں کے موقف کی فقہی اور آئینی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔
تاہم یہ غور ضرور کر لیں کہ کیا موجودہ حالات میں یہ بحث اٹھانا مفید ہوگا! میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اور بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ اس صورت حال میں ایک نئی اختلافی بحث کھڑی کر دینا مناسب نہیں۔ علم اور خاص طور پر علم دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں ایک بڑا اعزاز ہے، وہاں ایک مقدس امانت بھی ہے۔ اس کو استعمال کرنے میں انتہائی احتیاط اور ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کسی کے علم کا استعمال اس انداز سے ہو کہ امت مسلمہ کو اس کا نقصان یا پاداش برداشت کرنا پڑے تو شاید یہ علم کا بہتر استعمال نہیں۔ مزید مشورہ برادر مکرم جناب مولانا زاہد الراشدی اور اپنے جد محترم سے فرما لیں۔
والسلام
ڈاکٹر محمود احمد غازی
نائب رئیس الجامعہ
(۲)
۱۱؍ اگست ۲۰۱۰ء
برادر عزیز ومکرم جناب مولانا محمد عمار خان صاحب ناصر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
گرامی نامہ مورخہ ۲۶ جولائی کل سفر حرمین سے واپسی پر دیکھا۔ دعوت کا شکریہ۔ جزاکم اللہ
۳۰؍ ستمبر کو جمعرات ہے اور عدالتی مصروفیت کا دن ہے۔ میں اتوار کے روز صبح کے وقت دستیاب ہو سکتا ہوں۔ آپ ستمبر/شوال کے مہینہ میں کوئی سا اتوار رکھ لیں۔
والد مکرم کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ آپ کی تحریر بابت تولیت بیت المقدس کیا الگ سے بھی چھپی ہے؟ اس کی ایک نقل درکار ہے۔
والسلام
مخلص
محمود احمد غازی
بنام: محمد رضا تیمور
۱۹؍ اکتوبر ۲۰۰۷ء
برادر مکرم جناب محمد رضا تیمور ایم فل
السلام علیکم وررحمۃ اللہ وبرکاتہ
گرامی نامہ ملا۔ ممنون ہوا۔ جزاکم اللہ!
اس سے خوشی ہوئی کہ آپ کو محاضرات کا یہ سلسلہ پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قارئین کے لیے نافع اور ناچیز مولف کے لیے توشہ آخرت بنائے۔
آپ شوق سے ان کی تلخیص کیجیے۔ مناسب یہ ہوگا کہ پہلے کسی رسالہ میں ایک ایک محاضرہ شائع کرتے رہیے۔ قارئین کے تبصرہ اور رد عمل سے افادیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے گوجرانوالہ کا الشریعہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلے مولانا زاہد الراشدی سے استمزاج کر لیں۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
بنام: شبیر احمد خان میواتی
۰۰۔۹۔۴
برادر مکرم جناب مولانا شبیر احمد خان صاحب میواتی زیدت معالیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
گرامی نامہ مورخہ ۱۷؍۸؍۲۰۰۰ء موصول ہوا۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، ان کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعوات صالحہ میں یاد فرماتے رہیں۔
حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے لیے میرے بھی وہی احساسات ہیں جن کا آپ نے اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کرے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔
والسلام
مخلص
محمود احمد غازی
بنام: مولانا حیدر علی مینوی
برادر مکرم ومحترم جناب مولانا حیدر علی مینوی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے کہ آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ میں ایک عرصہ دراز سے آپ کو یہ عریضہ ارسال کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن میرے پاس آپ کا پتہ نہ تھا۔
اگر بہ سہولت ممکن ہو تو استاذ جلیل حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مینوی رحمہ اللہ کی تالیف جواہر الاصول کے دو نسخے ارسال فرما دیں۔
میں یہاں اگست کے اوائل تک مقیم ہوں۔ پھر قطر واپس جانا ہے جہاں میں آج کل مقیم ہوں۔
والسلام
نیاز مند
محمود احمد غازی
بنام: نعمت اللہ سومرو
مورخہ ۲؍اکتوبر ۱۹۹۱ء
برادرمکرم ومحترم جناب نعمت اللہ سومرو صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے کہ آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آپ کا خط مورخہ ۲۱؍ ستمبر موصول ہوا کہ آپ کے علاقے میں امن وامان کی صورحال بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد از ہماری ان مشکلات کو دورفرما دے۔
یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ شاہ عبداللطیف لائبریری کے اہتمام میں بہت سے دینی پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ تعمیری کوششیں بالآخر نتیجہ خیز ثابت ہوں گی اور آپ اسلام کے پیغام امن ومساوات کو عام کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں اکیڈمی اپنے وسائل کے مطابق آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہے۔
قطرٹیلی ویژن کے جس پروگرام کاآپ نے ذکر کیا ہے، وہ پہلے سے اکیڈمی میں موجود ہے اور اس کو اردو میں منتقل کرانے کی تجویز زیر غور ہے۔
والسلام مخلص
محمود احمد غازی
مکاتیب ڈاکٹر محمد حمیدؒ اللہ بنام ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ
ادارہ
ترتیب : ڈاکٹر حافظ محمد سجاد
(۱)
ڈاکٹر محمد حمید اللہؒ عالم اسلام کے نامور محقق، مفکر اور سیرت نگار تھے۔ آپ کی علمی، فکری، تحقیقی وتصنیفی زندگی تقریباً اسّی پچاسی سال کے طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا تعلق خاندانِ نوائط سے تھا۔ نوائط کا نسبی تعلق عرب کے معزز قبیلہ بنو ہاشم کی ایک شاخ سے تھا۔ یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ نوائط نے حجاج بن یوسف کے ظلم وستم سے تنگ آکر ہجرت کی اور یہ خاندان جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر آ کر آباد ہو گیا تھا۔یہ خاندان اپنی دین داری، شرافت اور علمی رجحانات وخدمات کے لحاظ سے بہت معروف ومشہور ہے (۱)۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ۱۶ محرم ۱۳۲۶ ہجری بمطابق ۱۹ فروری ۱۹۰۸ بروز چہار شنبہ کو فیل خانہ جو کہ حیدر آباد (دکن) کا قدیم محلہ تھا، میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو محمد خلیل اللہ تھا جو کہ مدد گار معتمدمال گزاری حیدر آباد تھے اور والدہ کا نام بی بی سلطان تھا۔ آپ کی پانچ بہنیں اور تین بھائی تھے۔ ایک بھائی کابچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ بہنوں کے نام امۃ العزیز بیگم، امۃ الو ہاب بیگم، امۃ رقیہ بیگم ، امۃ الصمد بیگم، حبیبۃ الرحمن اور بھائیوں کے نام محمد صبغت اللہ ، محمد حبیب اللہ اور محمد غلام احمد ہیں۔
ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تعلیم کا آغاز گھر سے دینی تعلیم سے ہوا۔ ان کی رسم بسم اللہ والد محترم نے پڑھائی۔ کچھ عرصے تک خود بیٹے کو درس دیتے رہے۔ پھر حیدر آباد کی مشہور درس گاہ دارالعلوم میں داخل کرایا جہاں وہ چھٹے درجے تک پڑھتے رہے۔چھٹی جماعت کے بعد انہیں مدرسہ نظامیہ میں شریک کرایا ۔ایک سال وہ وہاں پڑھتے رہے۔ اس زمانے میں انگریزی تعلیم حاصل کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر ڈاکٹر حمید اللہ انگریزی زبان کی اہمیت سے واقف تھے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم اپنے والد صاحب کی اجازت کے بغیر حاصل کرنا شروع کی۔
ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے بعد ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے جامعہ عثمانیہ میں داخلہ لیا۔ ۱۹۲۸ء میں ڈاکٹر صاحب نے جامعہ عثمانیہ سے فقہ میں بی اے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۰ سال تھی۔ ۱۹۳۰ء میں ایم اے کا امتحان درجہ اوّل میں پاس کیا اور اسی سال ایل ایل بی بھی کر لیا۔ جامعہ عثمانیہ میں تحقیقات علمیہ کے لیے علیحدہ شعبہ ۱۹۳۰ء میں قائم کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس شعبہ کے پہلے طالب علم تھے۔ ان کی تحقیق کا موضوع ’’اسلامی و یورپی قانون بین الممالک کا تقابلی مطالعہ‘‘ تھا۔ ایم اے میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے پر ڈاکٹر صاحب کو جامعہ عثمانیہ سے دو سال کے لیے ۷۵ روپے ماہوار وظیفہ ملا تھا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے جامعہ عثمانیہ سے درخواست کی کہ انہیں تحقیقی کام کے لیے مواد جمع کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے اور وہاں ان کا وظیفہ بھی جاری رکھا جائے جو جامعہ عثمانیہ نے قبول کی ۔
حصول علم اور تحقیق کا شوق ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو یورپ لے گیا جہاں کی لائبریریوں اور درس گاہوں سے آپ نے خوب استفادہ کیا۔ اکتوبر ۱۹۳۲ء میں جب وہ تحقیقی کام کے سلسلہ میں استنبول میں تھے توجرمنی کی بون یونیورسٹی کے پروفیسر کرنیکو نے ان کو بون آنے کی دعوت دی۔ جامعہ عثمانیہ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا مقالہ بون یونیورسٹی کو پیش کر سکتے ہیں۔ بون یونیورسٹی میں قیام کے دوران مخطوطات سے استفادہ کیا۔ برلین میں بعض نادر ونایاب مخطوطات دریافت کیے۔ بون یونیورسٹی میں ۱۹۳۳ ء میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا تحقیقی مقالہ ’’اسلام کے بین الاقوامی قانون میں غیر جانب داری‘‘ کے موضوع پر پیش کیا۔ اس مقالہ پر آپ کو ڈی فل کی ڈگری عطا کی گئی۔ اس کے بعد آپ پیرس آئے۔ ۱۹۳۴ء میں آپ نے پیرس کی مشہور ومعروف سور بون یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کے لیے داخلہ لیا۔ ان کے تحقیقی مقالے کا موضوع تھا ’’عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارت کاری‘‘۔ گیارہ مہینے کی قلیل مدت میں مقالہ مکمل کیا اور ۳۱ جنوری ۱۹۳۵ ء کو انہیں ڈی لٹ کی سند نہایت اعزاز کے ساتھ عطا کی گئی۔ جرمنی اور فرانس کی جامعات سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ارادہ ماسکو یونیورسٹی سے تیسری ڈاکٹریٹ حاصل کرنے کا تھا، لیکن آپ کے وظیفہ کی مدت ختم ہو گئی۔ا علیٰ ڈگریز کے حصول کے بعد ڈاکٹر صاحب وطن تشریف لائے اور مادر علمی جامعہ عثمانیہ سے وابستہ ہو گئے۔ جہاں وہ دینیات اور اسلامی قانون کی تعلیم دیتے رہے ۔یہ سلسلہ ۱۹۴۸ تک جاری رہا۔
تقسیم ہند کے بعد ریاست حیدرآباد کا سقوط ہو گیا تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے پیرس کو اپنا مستقل رہائشی مقام بنانے کا فیصلہ کیا ۔ انہوں نے فرانس کے ممتاز ادارے نیشنل سنٹر آف سائیٹفک ریسرچ National Centre of Scientific Research میں شمولیت اختیار کر لی۔کچھ عرصہ ترکی میں مہمان پروفیسر کی حیثیت سے تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ ۱۹۵۷ء میں ڈاکٹرذ کی ولیدی طوغان نے (جو استنبول یونیورسٹی میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر تھے)۔ ڈاکٹر صاحب کو مہمان پروفیسر کی حیثیت سے مدعو کیا۔ ان کے لیکچروں میں طلبہ کے علاوہ تعلیم یافتہ افراد اور دانشوروں کی خاصی تعداد شریک ہوا کرتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ڈاکٹر صاحب کے علم و فضل اور سیرت وکردار کی شہرت سارے ملک میں پھیل گئی۔ پچیس برس تک وہ استانبول یونیورسٹی، ارض روم یونیورسٹی اور دیگر جامعات میں مہمان پروفیسر کی حیثیت سے جاتے رہے۔ وہ سال میں تین مہینے ترکی اور باقی ایام پیرس میں گزارتے تھے۔ یورپ کے قیام کے دوران ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے جرمنی اور فرانس کی یونیورسٹیوں میں تدریسی خدمات سر انجام دیں۔پیرس میں آپ نے مستقل قیام کیا۔ وہاں کتب خانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ پیرس کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے تحقیق کے میدان میں کار ہائے نمایاں سرانجام دیے۔
ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک بلند پایہ محقق ، عالم دین، ادیب اور داعی اللہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تحقیق، تصنیف وتالیف اور اسلام کی خدمت میں صرف کر دی۔ انہوں نے بے شمار علمی خزانہ ورثے میں چھوڑا ہے جو دین اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور قابل فخر سرمایہ ہے۔انہوں نے قرآن و حدیث ،فقہ و قانون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے متنوع و مختلف موضوعات پر تقریباً ایک ہزار مقالات اور ایک سو ستر وقیع کتب یادگار چھوڑی ہیں۔ محمد حمید اللہ کا علمی و فکری سرمایہ صرف ان کے مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتب و مقالات تک ہی محدود نہیں رہا۔ ان کے مکاتیب بھی علوم و معارف کا ایک وقیع گنجینہ ہیں۔ ان مکاتیب سے نہ صرف مختلف اسلامی علوم و فنون کے حوالے سے قیمتی و مفید معلومات فراہم ہوتی ہیں بلکہ ان سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ان کے اصول زندگانی ،ان کے عادات و معمولات اور ان کی گوناں گوں دلچسپیوں کا بھی پتہ چلتا ہے ۔
(۲)
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ۔ آپ عالم اسلام کے نامور سکالر، مفکر، اور داعی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں ۔ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ ڈاکٹر محمد حمیداللہ ؒ کی علمی و تحقیقی خدمات کے قدر دان تھے۔ ونوں صاحبان علم کی علمی دلچسپیاں فقہ اسلامی، اسلام کے قانون بین الممالک اور سیرت طیبہ میں تھیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ نے نہ صرف ڈاکٹر محمد حمیداللہ ؒ کی علمی مطالعات و تحقیقات سے استفادہ فرمایا بلکہ ان کو متعارف کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر غازی ؒ صاحب نے ڈاکٹر محمد حمیداللہ ؒ کی وفات پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا ۔
’’مجھے ذاتی طور پر ان سے ملنے کا ۱۹۷۳ء میں نیاز ہوا اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے آخری مہینوں تک جاری رہا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کے قلم سے کو ئی ایسی تحریر نہیں نکلی جو انہوں نے کبھی اپنے دستخط یا دستخط کے بغیر مجھے اس کے ارسال سے مشرف نہ فرمایا ہو۔ اس دوران میں با ر بار ایسے مواقع آئے کہ ڈاکٹر صاحب نے بعض زیر تحقیق معاملے میں مجھے اس کا مستحق سمجھا، اس قابل گردانا کہ مشاورت کا شرف عطا کر سکیں۔‘‘ (۲)
ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ نے ڈاکٹر محمد حمیداللہ ؒ کے حوالے سے اپنے تاثرات میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ
’’ڈاکٹر صاحب کے اس وقت میرے پاس ۱۲۴ خطوط محفوظ اور دستیاب ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ اور خطوط بھی کاغذات سے مل جائیں۔ ان خطوط کو مرتب کرنے کا پروگرام ہے اور ان خطوط کی تمہید میں یہ ساری یافداشتیں جو ابھی تک حافظے میں ہیں، لکھی نہیں گئیں، اس تمہید میں لکھنے کا پروگرام ہے۔ بظاہر تمہید بھی ۱۵۰۔۲۰۰ صفحے کی ہو گی۔‘‘ (۳)
ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ صاحب نے اپنے نام ڈاکٹر محمد حمیداللہ ؒ کے یہ خطوط کمپوز کروا لیے تھے اور اب وہ ان خطوط کا پس منظر بیان کرتے ہوئے تفصیلی حواشی لکھنا چاہتے تھے، مگر بیرونی سفر اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے یہ کا م مکمل نہ ہو سکا۔ راقم نے ڈاکٹر صا حب کے حکم پر ان خطوط کی پروف خوانی کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان خطوط میں جن علمی نکات کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے حواشی میں لکھ دوں اور جو امور آپ سے متعلق ہیں، ان کی آپ خود و ضاحت کردیں۔ آپ نے اس تجویز کو پسندکیا اور فرمایاکہ کو ئی وقت مقرر کر لیتے ہیں،مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔اس کے بعد ملاقات کی نوبت نہ آ سکی اور آپ اپنے رب کے حضور حا ضر ہو گئے۔
ماہنامہ ’الشریعہ‘ کی اس خصوصی اشاعت بیاد ڈاکٹرمحمود احمد غازیؒ کے لیے ابتدائی دس خطوط ہدیہ قارئین ہیں۔ تمام ۱۲۴ خطوط پر حواشی کا کام جاری ہے، ان شا ء اللہ شش ماہی معارف اسلامی کے خصوصی شمارے بیاد ڈاکٹرمحمود احمد غازی میں ان کو شائع کیا جائے گا۔
خط نمبر:۱
بسم اللہ الرحمن الرحیم
۱۷؍ ربیع الانور ۱۳۹۴ھ
مکرمی زاد مجدکم
سلام مسنون۔ آپ کا عنایت نامہ کل یہاں پاریس ہوکر آیا۔ ممنون ہوا ۔
اگر کسی شخص کو قابل طباعت فرانسسی آتی ہو اور مصارف طباعت کا بھی انتظام کرسکتا ہو تو :
الف) عشرہ مبشرہ میں سے ہر ایک کے حالات
ب) حضرت بلالؓ ،صہیبؓو سلمان فارسیؓ میں سے ہر ایک کے حالات
ج) ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے حالات
د) دیگر ممتاز صحابیاتؓ کے حالات
ھ) اخلاقی قصے کہانیان،لطائف،ضرب الامثال
و) اردو کے شہ کاروں کے ترجمے
ز) تصوف پر اچھی کتابیں جو خلاف شریعت نہ ہوں
غرض آغاز ہے، ابتدائی نوعیت کی کتابیں بھی نومسلموں اور ان کی اولاد کو درکار ہیں اور بلند پایہ کتابیں بھی، السعی منا والاتمام من اللہ ۔ کار دنیا کسے تمام نکرد۔
مجھے یہاں مئی کے اواخر تک رہنا ہے۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
خط نمبر:۲
بسم اللہ الرحمن الرحیم
۲۱ رجب ۱۳۹۴ھ
مکرمی دام لطفکم
سلام مسنون
آج صبح عنایت نامہ ملا،شکر گزار ہوں۔
آپ کا سوال فرانسسی تالیف کے متعلق ایساہے جس کا خودآپ ہی نے جواب دے دیا ہے کہ عبد القدوس صاحب آپ کی مدد فرمانے والے ہیں۔ دوسرے سوال کے سلسلے میں یہ محض حسن ظن ہے کہ فرنگستان میں ہر چیز تیار ملتی ہے، ضرورت بس ایک پوسٹ کارڈ یا ایروگرام کے لکھنے کی ہے۔ یورپ میں مردم شماری کے وقت کبھی مذہب دریافت نہیں کیا جاتا، کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں کتنے مسلمان ہیں۔
کافی عرصہ ہوا پروفیسر ماسین یوں Massignon نے سالنامۂ عالم اسلام Annuai nedu monde musulman شائع کرنا شروع کیا تھا۔ اس میں ہر قسم کے معلومات تھے۔ اب تو مؤلف کی وفات بھی ہو چکی ہے۔ معلومات کی ’’صحت‘‘ کا اندازہ اس سے کیجیے کہ انگلستان میں دس بارہ نو مسلم ہیں، فرانس میں ایک بھی نہیں!
فرانس میں آج کل پچیس تیس لاکھ مسلمان ہیں جن میں خاصے نو مسلم بھی ہیں۔ میرے اندازے میں شہرپاریس ہی میں دس ہزار سے کچھ زیادہ نو مسلم ہیں۔ یہاں فی الحال slam France-I نامی ایک فرانسسی ماہنامہ ہے۔ تین اسلامی انجمنیں قابل ذکر ہیں:
Centre Cultural Islamique,
Amicale des Musulmans
Association des Etudiants Islamiques
انگلستان میں سو سے زائد مسجدیں ہیں۔ پاریس میں اب بارہ پندرہ ہو چلی ہیں ۔
انگلستان میں کم از کم نو گرجا مسلمانوں کی مسجدوں کا کام دیتے ہیں تو پاریس میں دو۔ باقی فرانس میں مزید دو کا مجھے علم ہے، مگر ان خبروں کی اشاعت سے ہمیں مشکلیں ہی پیش آئیں گی کیونکہ ہر ملک وقوم میں تنگ نظر اورمتعصب لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ شور مچائیں تو روادار لوگ بھی ہاتھ روک لیتے ہیں۔
راوس کے مسلمان کے متعلق کوئی پندرہ بیس سال قبل فرانسسی وزارت خارجہ نے ایک کتاب شائع کی تھی۔ مؤلف کا نام Bennigsen ہے مگر اب اس کا ملنا ممکن نہیں۔
والسلام
محمد حمید اللہ
خط نمبر:۳
بسم اللہ الرحمن الرحیم
۱۷؍ محرم ۱۳۹۵ھ
مکرمی
سلام مسنون.عنایت نامہ ملا۔ شکریہ۔ پابہ رکاب ہوں۔
آپ کا سوال مجھے بھایا نہیں۔ کسی بھی موضوع کو لیا جاسکتاہے، اہمیت عنوان کو نہیں مندرجات کو ہوتی ہے۔ ہر موضوع پر کام ہو سکتاہے۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
خط نمبر:۴
بسم اللہ الرحمن الرحیم
۲۵ ذوالقعدہ۱۳۹۶ھ
مکرمی دام لطفکم
سلام مسنون۔ عید مبارک
عنایت نامہ ملا اور یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ آپ کی محترم و عزیز ہمشیرہ نے اپناکام مکمل کر لیاہے۔ میری مبارکباد پہنچائیں۔ تو قع ہے کہ یہ چھٹے (آخری) اڈیشن پر مبنی ہے ۔
اگر وہ چاہتی ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ میں بھی ترجمے پر ایک نظر ڈال لوں تو براہ کرم ارسال سے قبل مجھ سے پوچھ لیں۔ اگر وصولی کے زمانے میں، میں پاریس میں نہ رہوں تو بستہ بھیجنے والوں کو واپس ہو جائیگا۔ سمندری ڈاک دوماہ سے زیادہ لیتی ہے۔
مخلص
محمد حمید اللہ
مکرر
براہ کرم کبھی پارسل نہ بھیجیے۔ وہ لازماً چنگی خانہ جاتی ہے اورچنگی نہ بھی لی جائے تو اجرت کار بارہ فرانک (تقریباً چھتیس روپے) لی جاتی ہے۔ امید کہ خیال رکھا جائے گا۔
خط نمبر:۵
بسم اللہ الرحمن الرحیم
محترم زاد مجدکم ۶؍ محرم۱۳۹۸ھ
سلام مسنون۔ آپ کا عنایت نامہ استانبول والوں کی عنایت سے کل یہاں آیا، شکریہ۔ عزیز آپا جان کو میری مبارک باد فرمائیں۔ میں دو دن میں جرمنی کے سفر پر جارہا ہوں۔ دو ایک ہفتوں میں واپس آنے پر مکرر جنوبی فرانس جانا ہے۔ فروری میں ترکی کا سفر در پیش ہے۔ (اس سال استانبول کی جگہ ارضردم کی دعوت آئی ہے) اور وہاں کثیر سرکاری فرائض میں اس کا وقت نہ ملے گا کہ آپا جان کا کام کروں۔ اصل کتاب بھی ساتھ نہ ہوگی ( میں اشرف صاحب کو ساتواں اڈیشن تصحیح کے بعد ان کی فرمائش پر بھیج چکا ہو ں، معلوم نہیں چھپا یا نہیں) چھٹے اڈیشن میں عربی متن بہت غلط چھپے ہیں۔
ان حالات میں التجاء ہے کہ ساری کتاب ایک ساتھ اس طرح بھیجیں کہ وہ مثلاً جون کے آغاز میں فرانس آئے۔ احتیاطاُ پتہ لینڈ لیڈی کا لکھیے تاکہ میری غیر حاضری میں بھی ڈاکیا بستہ پہنچا دے۔
خدا کر ے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں ۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
LA CONCIERGE
POUR Mr. Hamidullah
4, Rue de Tournan
25006- Paris/France
خط نمبر:۶
بسم اللہ الرحمن الرحیم
۲۷؍ربیع الانور ۱۴۰۰ھ
مخدوم و محترم متعنا اللہ بطول حیاتکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ نے اس ناچیز کی جو قدر افزائی اور مہمان نوازی اسلام آباد میں فرمائی، اس پر ممنونیت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں پاتا۔ حفظکم اللہ وعافاکم۔
بہاولپور کا سفر متعین ہوچکا ہے۔ ان شاء اللہ پاریس سے ۵مارچ کونکلوں گا اور ایک دن کراچی میں آرام لے کر آگے روانہ ہو جاؤں گا۔ ۸ تا ۲۱ مارچ وہاں درس ہیں۔ پھر فرانس واپسی ہے۔ ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آیا مختصر قیام ہی کے لیے سہی، اسلام آباد آسکوں گا۔ سب احباب کوسلام مسنون عرض کرتا ہوں۔
غازی صاحب آپ کے رفیق تھے جن کے ہاں آپ کی ہمراہی میں رات کی دعوت ہوئی تھی۔ بعض چیزیں دریافت کی تھیں جوذیل میں درج ہیں۔ ان سے فرمادیں تو نوازش ہوگی:
Paul Coudere, Le Calwdrier مطبوعہ پاریس کے مطابق یہودیوں نے کالدیاوالوں سے تقویم لی۔ ان کے مہینے اب یہ ہیں:
1. Tishre 2. Marsahevan 3. Kislew. 4. Tebet 5. Sebat 6. Adar 7.. Nisan
8. Iyar 9. Sivan 10. Tamoug 11. Ab 12. Elul
یہودیوں کی Civil تقویم تِشری کے مہینے سے شروع ہوتی ہے ،خزاں میں ،اوریہ مہینہ کبھی اکتوبر اورکبھی ستمبر میں آتاہے کیونکہ مہینے توقمری ہوتے ہیں لیکن نسی کر کے تیرھواں مہینہ وقتاً فوقتاً ماہ آدار کے بعد بڑھاتے ہیں اور یہ زائد مہینہ Veadar کہلاتا ہے ۔ مگر مذہبی تقویم میں سال کا آغاز ماہ نیساں سے ہوتاہے جو مصر سے نکلنے اور دریا عبور کرنے (Peskha) کی یاد سے مربوط ہے ۔نسی کے باعث ماہ نیساں اپریل سے کبھی زیادہ دور نہیں ہوتا۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
خط نمبر:۷
بسم اللہ الرحمن الرحیم
محترمی ۲۱؍شعبان۱۴۰۰ھ
سلام مسنون ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ
نوازش نامہ ملا۔مضمون کے ص:۷ پر Rune Genu نہیں Rene Guenon۔ ص:۱ پر عاقل نہیں آکؤیل Aquil قلینڈی نام ہے۔ ص:۱ پر اپنے محل میں ’’کی جگہ‘‘ اپنے محل کے قریب۔ ص:۳ مشل والی شاں، امیشل مصطفی وال ساں vichel Valsam ہے۔ ص: ۵ پر ’’اس پادری کو چند سال قبل ایک پادری کے قتل کے جرم میں‘‘ کو ’’ایک عورت کے قتل کے جرم‘‘ پڑھئے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لاہور چند سال قبل وہاں کے وزیر اعظم کی صدرات میں دیے ہوے لکچر کا خلاصہ کسی کا لکھا ہوا ہے، مگر استدعا ہے کہ شائع نہ فرمائیں۔ آج فرانس میں پوپ کے حکم سے حکومت کی سیاست بدل گئی ہے، تعصب تو عناد اور دشمنی میں مبدل ہوگیا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ جومسلمان یہاں متوطن ہوگئے ہیں، لیکن اجنبی قومیت کے ساتھ، ان میں سے ہر سال پینتیس ہزار کو اپنے اصلی وطن کو واپس جانے پر مجبور کیا جائے۔ اس کا اطلاق خاص کر بیس پچیس لاکھ الجزائر یوں پر ہوتا ہے اوران کی جگہ پرتگالیوں کو مزدوری کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ فرانس میں نو مسلموں کی روز افزوں کثرت سے کلیسا پریشان ہو گیا ہے۔ یہودی اور کمیونسٹ بھی حیران ہیں۔ گذشتہ ہفتے ایک کمیونسٹ اخبار کے ایڈیٹر نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کے نامہ نگار کو اس موضوع پر سوالات کا انٹریو میں جواب دوں۔ میں نے ٹال دیا اور ادب سے کہا کہ جامع مسجد کو جا کر وہاں کے ناظم سے پوچھ لو۔
ان حالات میں قطعاً مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ دشمنوں کو معلومات مہیا کیے جائیں۔ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
مکرر:
کیا حدیث قدسی پر کسی مطبوعہ علمی کام کا آپ کو کوئی علم ہے؟ میری ایک نومسلم شاگرد عائشہ اس پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھ رہی ہے۔ Zwenier کا مضمون مسلم ورلڈ میں اور Mouton کمپنی کی شائع کردہ حالیہ ا نگریزی کتاب سے میں واقف ہوں۔ معلوم نہیں اردو فارسی، عربی، ترکی میں کوئی چیز آپ کے علم میں ہو۔
خط نمبر: ۸
بسم اللہ الرحمن الرحیم
محترمی دوشنبہ ،۹؍رمضان المبارک ۱۴۰۰ھ
سلام مسنون ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عنایت نامہ ملا۔ خیروعافیت کی اطلاع سے مسرت ہوئی۔
اگر موقع ہو تو الجزائر کے ذمہ دار لوگوں سے کہئے کہ مراکش میں جامع قرویین ہے، تونس میں جامع زیتونہ ہے ، مصر میں الازہر، مگر الجزائر میں کوئی اسلامی بڑی درسگاہ نہیں اور الجزائر یوں کو اپنے ہمسایوں کے ہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دورِ استعمار میں پیدا شدہ اس خلا کو اب جلد سے جلد پر کرنا چاہئے کہ آدمی کو پیٹ بھی ہے اور دماغ بھی۔ صرف کسی ایک کو کِھلا ئیں تو دوسرا بھوکا مر جائیگا۔
ستمبر کے اواخر تک تو سفر کا کوئی پرگرام نہیں ہے اِلّا ما شاء اللہ۔ آپ کی تشریف آوری سے مسرت ہوگی، لیکن یونیورسٹی کے اساتذہ ابھی گرمائی تعطیلوں میں غائب ہی رہیں گے۔ کوشش فرمائیے کہ کسی اتوار کو یہاں رہیں تاکہ جمعیۃ الطلاب الاسلامیین کے ہفتہ وار اجلاس میں (جو صرف اتوار کو ہو سکتاہے) تشریف رکھ سکیں اور ان کو مخاطب فرما سکیں۔
رمضان مبارک، یوسف صاحب اور ان کی عزیز اہلیہ کو بھی میرا سلام فرمادیں۔
کیا اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد ع یا م شائع ہوگئی ہیں؟ عرصے سے زیر طبع تھیں۔ جواب کی کوئی جلدی نہیں۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
خط نمبر:۹
بسم اللہ الرحمن الرحیم
۲۳؍ذی القعدہ ۱۴۰۰ھ
محترم ومکرم زاد مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ایک ہفتے کی پرواز کے بعد الحمد للہ آج آپ کا عنایت نامہ پہنچ گیا۔خیروعافیت کی اطلاع سے مسرت بھی ہوئی اور اطمینان بھی ہوا، خاص کر ترکی کے انقلاب کے باوجود آپ کے لئے ازہر کے سفر کا موقع ملا۔ واللہ علیٰ مایشاء قدیر۔
افسوس ہوا کہ آپ پاریس کے کتب خانہ عام کو نہ جا سکے۔ اگر معلوم ہوتا کہ آپ کے رفیق اس میں دشواری محسوس کرتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ لے جاتا۔توپ کاپی سرائے کے سلسلے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دست مبارک کے متعلق جب میں نے دریافت کیا تھا تو بتایا گیا تھاکہ جب سلطان محمد فاتحؒ نے استانبول کو فتح کیا، مشہور حدیث نبوی کی حقانیت ثابت کی ۔ تو وہاں قیصر روم کے خزانۂ خاص الخاص میں یہ مساعد بھی ملا۔ (معلوم نہیں کیوں، اس کو ادب سے دفن کرنے کی جگہ محفوظ رکھا ہے؟) باقی کس حد تک وہ صحیح ہے اور اس کی تاریخ و سرگزشت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانے۔
آپ کی مجلس کے سرنامہ پر موناگرام میں ’’ تعاونوا علی البر والتقویٰ‘‘ کی آیت پاک کے متعلق ہے۔ ( سورہ ۵ آیت ۲) آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ کفار سے برتاؤ کے متعلق ہے، ’’ما بین المسلمین‘‘ طرز عمل کے لیے نہیں۔ اس آخر کے لیے اِنَّمَا المَؤمِنُوْنَ إخْوَۃٌ وغیرہ آیتیں ہیں۔ حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (تین دن سے قطع مومن نہ کرنا چاہئے وغیرہ)
کیا آپ کو ایک زحمت دے سکتاہوں ؟ لاہور کے محمد اشرف صاحب نے میری کتاب چھاپی ہے۔ وہ یہاں نہیں ملتی ۔ اس کی مجھے شدید اور فوری ضرورت ہے ۔کیا وہ اسلام آباد میں مل سکتی ہے ؟اس کا ایک نسخہ ہوائی ڈاک سے، بل کے ساتھ روانہ فرما سکیں تو خوشی کا باعث ہوگا اور ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔
کار لائق سے یاد فرمائیں۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
خط نمبر:۱۰
بسم اللہ الرحمن الرحیم
سہ شنبہ،۴؍ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ
محترم ومکرم زاد مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید مبارک
کتاب ابھی ابھی پہنچ گئی، دلی شکریہ۔
یہ چوری کا ایڈیشن ہے۔ پہلی دفعہ دیکھ رہاہوں۔ اللہ ہم لوگو ں کو اسلام فروشی سے بچائے۔ مزید برآں اجازت نہ مانگنے میں اس میں ایک مضرت یہ بھی ہے کہ کتاب کی تازہ تصحیحیں اور اصلاحیں نہیں ہوئی ہیں اور پرانی غلطیاں برقرار رہتی ہیں۔
بہر حال آپ کا دلی شکریہ ۔ میں نے کراچی میں ایک رشتہ دار کو لکھ دیا ہے کہ کتاب کی قیمت اور ڈاک کے مصارف آپ کو منی آرڈر سے بھیج دیں۔
میں ان شاء اللہ عیدالاضحی جزیرہ ریونیوں میں گزارو ں گا۔ دو ایک دن میں جارہا ہوں اور دو ہفتوں میں واپسی ہوگی۔ واللہ المستعان۔
نیاز مند
محمد حمید اللہ
حواشی و تعلیقات
۱۔ عمری، محمد یوسف کوکن، مولانا، خانوادہ قاضی بدرالدولہ، دارالتصنیف مدراس، ۱۹۶۳،ج۱/ص ۲۱۔۲۲
یوسف کوکن نے قاضی بدرالدولہ کے خاندان اور ان کے علمی کارناموں سے متعلق دو جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ’’خانوادہ قاضی بدرالدولہ ‘‘کے نام سے لکھی ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں نائطی خاندان کے بارے میں لکھتے ہیں:
’’ قاضی بدرالدولہ کا خاندان نائطی کہلاتا ہے جو اپنے حسب ونسب ،عزوشرف، دینی ودنیوی وجاہت اور خصوصی رسم ورواج کے لحاظ سے خاص کر جنوبی ہند میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ نوائط جمع ہے نائط کی اور یہ لفظ’’ط‘‘ اور ’’ت‘‘ کے ساتھ دونوں طرح لکھا جاتا ہے۔ قدیم مورخین اور تذکرہ نگار ’’ت‘‘ سے ہی لکھا کرتے تھے‘‘۔
۲۔ غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، علم و عمل کا پیکر۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہؒ در شش ماہی معارف اسلامی، علامہ اقبال اوپن یو نیو رسٹی اسلام آباد،۲۰۰۳ء، جلد ۲ شمارہ ۲ ص۳۹۵
۳۔ایضا
ڈاکٹر غازیؒ کے انتقال پر معاصر اہل علم کے تاثرات
ادارہ
ترتیب: ڈاکٹر سید عزیز الرحمن
پروفیسر عبدالقیوم قریشی
(سابق وائس چانسلر، اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور)
ڈاکٹر محمود احمد غازی تمام اخلاق حمیدہ سے متصف انسان تھے۔ ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ’’بزم دم گفتگو گرم دم جستجو‘‘۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کو بات سمجھانے کا ایسا ملکہ اللہ نے عطا کیا تھا کہ ججوں کی تربیت کے دوران ہرجج کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مرحوم سے استفادہ کرے۔
پروفیسر فتح محمد ملک
(ریکٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد،سابق چےئرمین مقتدرہ قومی زبان)
یقین نہیں آتا کہ ڈاکٹر غازی ؒ ہم سے جدا ہوگئے ہیں۔ مقررین نے ان کے بارے میں یہ تو بتا دیا کہ وہ وفاقی وزیرتھے، لیکن ایک بات جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی، وہ کسی نے نہیں بتائی اور وہ یہ تھی کہ مرحوم ایک ڈکٹیٹر سے نظریاتی اختلاف رکھتے تھے اور جب اس ڈکٹیٹر نے دینی حکمت عملی میں تبدیلی کی تو ڈاکٹر غازی نے یہ کہتے ہوئے وزارت سے استعفا دے دیا کہ مجھے یہ تبدیلی منظور نہیں۔ ڈاکٹر غازی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔
ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری
(ڈائریکٹر ادارۂ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد)
اسلامی تعلیمات ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھیں۔ دیانت، امانت، ورع و تقویٰ میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ میں ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ : He is punishing the onesty۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ نے اپنی ملازمت کے آخری دن دفتر کی گاڑی استعمال نہ کی اورا س کا عذر یہ پیش کیا کہ میں اب صدر نہیں ہوں۔ نہایت وسیع مطالعہ کے حامل تھے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن خود غازی صاحب مرحوم نے کہا کہ میں نے ’’کتاب الام‘‘ سات مرتبہ بالاستیعاب پڑھی ہے۔ تاریخ، سیرت، فقہ، حدیث، علم الکلام، فلسفہ، ادب اور شعرسب میں ان کو دلچسپی تھی۔ وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ مرحوم یونیورسٹی کی صدارت کی گراں بار ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ چھ گھنٹے روزانہ تدریس کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا انجام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں۔
جسٹس (ر) خلیل الرحمن خان
(سابق ریکٹربین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد)
ڈاکٹر محمود احمد غازی کا علم سمندر کی سی گہرائی رکھتا تھا۔ اخلاق کریمانہ سے متصف تھے اور ہر ملنے والے سے ایسے ملتے تھے گویا وہ کوئی دیرینہ شناسا ہو۔ میں نے سود کیس چھ ماہ سننے کے بعد جو جج منٹ لکھی، اگر غازی مرحوم کی معاونت نہ ہوتی تو میرے لیے وہ لکھنا ممکن نہ تھا۔ غازی مرحوم اس ورثے کے امین تھے جو سرتاپا علم ہی علم تھا۔ والد کی طرف سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ سے اور والدہ کی طرف سے مولانا الیاسؒ بانی تبلیغی جماعت سے قرابت داری تھی۔اسلامی یونیورسٹی میں حسن بن طلال، مہاتیر محمد اور نیلسن منڈیلا کے نائبین کی آمد مرحوم ہی کا کارنامہ تھا جس نے پور ی دنیا میں یونیورسٹی کو پہچان بخشی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔
ڈاکٹر ایس ایم زمان
(سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، اسلام آباد)
’’ موت العالم موت العالم‘‘ کی ضرب المثل ڈاکٹر غازی مرحوم پر صادق آتی ہے۔ ان کے اخلاق میں صداقت کا پہلو برملا تھا۔ میں نے غازی صاحب کے ساتھ طویل رفاقت میں ان کو انتہائی دیانت دار پایا اور ایسا کہ اس پایے کی کوئی ایک مثال ملنا بھی آج پورے ملک میں ممکن نہیں۔ علم میں ان کا ثانی اور ہم سر تو پیدا ہو سکتاہے، لیکن دیانت، امانت، صداقت اور خلوص میں ان جیسا سپوت اس مٹی کو اب ملنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمن
(ڈائریکٹر، دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد)
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ ایک ہمہ جہت و ہمہ پہلو شخصیت تھے اور قدیم و جدید علوم کا حسین امتزاج تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم دین کی ترویج و اشاعت، اقدار اسلامیہ کے فروغ ا ور ملک و ملت کی بھلائی کے لیے صرف تھا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اہل علم سے اپنی علمیت کا لوہا منوایا تھا اور انتہائی کم عمری میں بڑے بڑے اسکالرز کے درمیان استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کا وصال کسی ایک طبقہ، خاندان یا ایک ملک کا نقصان نہیں، پوری ملت اسلامیہ کا نقصان ہے۔ تقویٰ، طہارت، امانت اور دیانت کا مجسم پیکر تھے۔ اللہ ان کی قبر پر اپنے انوار اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔
ڈاکٹر ممتاز احمد
(ایگزیکٹوڈائریکٹراقبال، انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ)
ڈاکٹر محمود احمد غازی علم اور حلم، دونوں میں ممتاز تھے۔ ان کے علم کے بارے میں اظہار خیال کرنا میرے لیے گستاخی کی بات ہے۔ مرحوم بہت محبت کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے انسان تھے۔ ہمیشہ خوشی، گرم جوشی اور تعلق خاطر سے ملا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید
(رئیس الجامعہ دارالعلوم، زاہدان)
مایہ ناز دانشور اور گراں قدر عالم دین جناب ڈاکٹر محموداحمد غازی رحمہ اللہ جو عالم اسلام کی نامور شخصیات اور علمی سرمایوں میں سے تھے، ان کے انتقال کی افسوسناک خبر نے ہمیں سخت غم زدہ اور متاثر کیا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ مختلف موضوعات میں دسیوں تصانیف کے علاوہ متعدد سیمینارز اور کانفرنسز میں شرکت کر کے مغربی دنیا میں اسلام کا تعارف پیش کرتے تھے۔ مرحوم نے ۲۰۰۹ء کی بہار میں ایران اور دارالعلوم زاہدان کا تفصیلی دورہ کیا۔ آپ ایک ہفتے تک ایران کے ممتاز علمی ادارہ دارالعلوم زاہدان میں مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے رہے۔
ریجنل دعوۃ سنٹر کراچی کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنس
آغا عبد الصمد
وفاقی شرعی عدالت کے جج، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین، سابق وفاقی وزیر وسابق ڈائریکٹر جنرل دعوۃ اکیڈمی وسابق صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آبادڈاکٹر محمود احمد غازی کی یاد میں ریجنل دعوۃ سنٹر (سندھ) کراچی اور دارالعلم والتحقیق کراچی کی جانب سے دارالعلم والتحقیق میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیاگیا جس سے انجینئرسید احتشام حسین، ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی، ڈاکٹر احسان الحق، مولانا ولی خان المظفر، آغا نور محمد پٹھان اور ڈاکٹر سید عزیز الرحمن نے خطاب فرمایا، جبکہ صدارت سید فضل الرحمن (ڈائریکٹر دارالعلم والتحقیق) نے کی۔پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کی علمی، تحقیقی، قانونی اور عدالتی خدمات اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔
تعزیتی اجلاس کا افتتاح قاری محمدیاسین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سید عزیز الرحمن انچارج ریجنل دعوۃ سنٹر (سندھ) کراچی نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج انتہائی افسوس اور رنج کے ساتھ عالم اسلام کی انتہائی ممتاز، انتہائی محترم اور انتہائی وقیع شخصیت، ہمارے اور ہم جیسے عالم اسلام کے بہت سے اداروں کے سرپرست جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک تعزیتی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یقیناًہر چیز پر حاوی ہے۔ چند روز پہلے تک ہم یہاں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سننے کے لیے جمع ہوتے تھے اور آج ان کی یاد میں ان کی تعزیتی تقریب کے لیے جمع ہیں۔ انہوں نے غازی صاحب کی سوانح حیات پر مفصل روشنی ڈالی اور ان کی علمی خدمات کو بیان کیا۔ انہوں نے کہاکہ ڈاکٹر محمود احمد غازی جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی موت پورے عالم کا نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسی صاحب علم وبصیرت، صاحب تفقہ، متوازن ومتواضع اور جدید وقدیم کی جامع شخصیت عالم اسلام میں اب نظر نہیں آتی۔
آغانورمحمد پٹھان ریزیڈنٹ ڈائریکٹر اکادمی ادبیات کراچی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرصاحب اسلام اور علم وادب کے جدید تقاضو ں سے ہم آہنگ تھے۔ ان کی اصل خوبی یہ تھی کہ ایک متواضع اور صاحب علم شخصیت تھے۔ وہ اپنی ذاتی محنت کی بنا پر بڑے بڑے مناصب تک پہنچے۔ وہ ہفت زباں ادیب تھے، بے مثال مقرر تھے اور ایک ایسی سطح پر تھے جہاں وہ بیک وقت مختلف کام کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہر ایک کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے۔ وہ بیک وقت منتظم، مدبر، مدیر، محقق اور مصنف تھے۔ ان کا انتقال ایک ایسے وقت میں ہوا جب امت مسلمہ کو ان کی شدید ضرورت تھی۔
پروفیسرڈاکٹر حافظ احسان الحق (صدر شعبہ عربی، جامعہ کراچی) نے تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غازی صاحب نے دنیا کی مختصر زندگی جو بہت بڑا کام کیا تو اس کام میں نہ صرف ان کی Will powerیا قوت ارادی یا ذاتی محنت کا دخل تھا بلکہ وہ اللہ کی دین تھی اور وہ یقیناًاللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ ان سے میرا تعلق طالب علمانہ تھا۔ ان کے بعض بیرونی اسفار میں ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کے اسفار کا ان کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، اپنی تمام ذمے داریاں بحسن وخوبی سرانجام دیتے تھے۔ غازی صاحب بڑے سادہ مزاج آدمی تھے۔ پروٹوکول کا تقاضا نہیں کرتے تھے۔ بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان پر علم کا خصوصی نزول ہوتا تھا۔انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ اعزاز کی با ت تھی کہ مجھے پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں ان کے دست مبارک سے شیلڈ ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے تھے اوران کو آگے بڑھاتے تھے۔ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ غازی صاحب اعلیٰ اخلاق کا مجسمہ اور صاحب تقویٰ شخص تھے۔ ان کی موت ایک عظیم نقصان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلوبلائزیشن مسلمانوں کے لیے بڑاچیلنج ہے۔ ہمارے دانش ور یک رخے ہوگئے ہیں۔ غازی صاحب مشرقی علوم کے اصل مصادر کے ساتھ ساتھ مغربی علوم سے بھی واقف تھے، ان کاوژن بہت وسیع تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور سوگواران کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔
پروفیسرڈاکٹر عبدالشہید نعمانی (سابق صدر شعبہ عربی، جامعہ کراچی) نے تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میرے لیے بڑا عجیب موقع ہے کہ میں اپنے ایک دیرینہ دوست اور ساتھی کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اور غازی صاحب نے ایک ساتھ حفظ کیا اور درجہ رابعہ تک جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں غازی صاحب اسلام آباد منتقل ہوگئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی بچپن سے یہی سوچ تھی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لہٰذا اس کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے۔ انہوں نے کلاس میں ایک سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اس کے صدر اور میں وزیراعظم تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ذہین انسان تھے اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی تربیت ان کے والدین کے اخلاص کا نتیجہ تھی۔ ان کے والدین چاہتے تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر یا انجینئر بناتے، لیکن انہوں نے غازی صاحب کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے وقف کیا۔ نعمانی صاحب نے مزید کہا کہ غازی صاحب نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے دینی ودنیوی دونوں علوم پر دسترس حاصل کی اور اپنی محنت، شوق اور لگن سے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ انتظامی عہدوں کے باوجود وہ تعلیم پر توجہ دیتے تھے، ان کا بیشتر وقت تعلیم وتعلم میں گزرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تمام صلاحیتوں کے جامع تھے۔ ان کی نظر بڑی وسیع تھی۔ اسلامی بینکنگ میں دونوں علوم کے ماہر بہت کم ہیں، لیکن غازی صاحب نے اس موضوع پر بڑ اکام کیا۔ بینکنگ کی تاریخ اور اس کی بنیاد پر ان کی نظر تھی۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے اس کا بے لاگ تجزیہ کیا ہے اور نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ اس کا حل بھی پیش کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، ان کے افکار کو مرتب کیا جائے اور ان کے علمی ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔
المظفر ٹرسٹ کے سر پرست مولانا ولی خان المظفرنے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ سب سے پہلے میں ڈاکٹر سید عزیزالرحمن کا شکر گزار ہوں جنھوں نے اس نشست کا انعقاد کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کئی نشستیں اب تک ہوجانی چاہییں تھیں ۔غازی صاحب کی سوچ، فکر، نظریہ اور ان کی آفاقیت، ہمہ جہتی اور ہمہ گیریت کے حوالے سے کئی پروگرام اور میڈیا پر ان کا پرچار ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہاکہ ڈاکٹرغازی صاحب، احمد دیدات، علی میاں اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس آخری دور میں امت مسلمہ کا وہ عظیم سرمایہ تھے کہ اب ان کی مثال دنیا کو شاید ہی مل سکے۔ بڑی مدت بعد ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ ان حضرات نے اپنے اپنے میدانوں میں کارہاے نمایاں سرانجام دیے۔ انہوں نے کہا کہ غازی صاحب سے میری کئی ملاقاتیں صدر وفاق المدارس مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے ہوئیں۔ ا پنے ادارے جامعہ فاروقیہ کے معہداللغۃ العربیہ کے حوالے سے میں ان سے ملتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ا ن کے اندر گہرائی بھی تھی اور گیرائی بھی تھی۔ حافظہ بے مثال تھا۔ انہوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو اہل ثابت کیا۔ سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ عربی ادبیات میں ان کو کمال حاصل تھا۔ ہندوستان میں ابوالحسن علی ندوی اور پاکستان میں غازی صاحب ایک پایے کے لوگ تھے۔ دینی مدارس کو وہ جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے تھے۔ ماڈل دینی مدارس ان کا منصوبہ تھا اور اس کے لیے انہوں نے نصاب بھی ترتیب دے دیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت مسلمہ کی عبقری شخصیات سے سبق حاصل کریں، علم میں رسوخ پیدا کریں اور امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔
تحریک فہم اسلام کے سربراہ انجینئر سید احتشام حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ڈاکٹر صاحب، صاحب علم آدمی تھے اور صاحب علم پر گفتگو کے لیے صاحب علم لوگ ہی درکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک عالم ساری زندگی علم کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہے اور شام زندگی کے قریب جب وہ سطح آب پر آتا ہے تو اس کے پاس کچھ سیپیاں، کچھ مونگے اور کبھی کبھار کچھ موتی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں چند خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جو فنا فی العلم ہوکر خود علم کے بحر بے کراں بن جاتے ہیں اور دنیا کو مستفید اور متاثر کرتے ہیں اور اگر میں کہوں کہ فنا فی العلم ہو کر ناپیدا کنار کو اگر آپ مجسم نام دیں تو ڈاکٹر محمود احمد غازی کہلاسکے گا۔
انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ماموں زاد بھائی تھے۔ ان سے ایک امت فیض یاب ہوئی۔ وہ نہایت جفاکش، محنتی اور درد دل رکھنے والے محقق، عالم، مفکر، داعی اور فقیہ تھے۔ پاکستان اور عالم اسلام کے لیے انہوں نے قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تصنیف وتحقیق کے میدان میں اپنا لوہا منوایا اور قومی، ملی اور دینی تحریکوں کے پشت پناہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کا آخری سفر جس طمانیت، اطمینان اور استقامت کے ساتھ پورا کیا، وہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا شمار ان چیدہ چیدہ افراد میں ہوتا تھا جو دور جدید کے رجحانات پر ناقدانہ نظر رکھتے تھے اور امت کو دینی قیادت فراہم کرسکتے تھے۔
تعزیتی ریفرنس میں زندگی کے مختلف طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریفرنس کااختتام جناب سید فضل الرحمن صاحب ڈائریکٹر دارالعلم والتحقیق کی دعا سے ہوا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی یاد میں رابطۃ الادب الاسلامی کے سیمینار کی روداد
ادارہ
۱۹ دسمبر ۲۰۱۰ء کو رابطۃ الادب الاسلامی پاکستان کے زیر اہتمام جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی یاد میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں ممتاز اہل علم واہل دانش نے ڈاکٹر صاحب کی حیات وخدمات کے مختلف پہلووں کے حوالے سے اپنے خیالات وجذبات کا اظہار کیا۔
جامعہ امدادیہ کے مہتمم مولانا مفتی محمد طیب نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علمی اور عملی کمالات کے حامل افراد ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ایسے حضرات کے راستے بھی ہمارے لیے راہنما راستے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے جامع صفات عطا فرمائی تھیں اور مختلف علمی طبقات ان سے استفادہ کر رہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا گوشت پوست اور جسم کی ہر چیز علم کی بنی ہوتی ہے اور ان کے اندر علم اس قدر راسخ ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے، علم ہی کی نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ مزاح کی بات کریں تو اس میں بھی علم کی چاشنی موجود ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس موضوع پربھی بات کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں پہلے سے تیار شدہ کوئی منضبط کتاب ہے جس کو وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے آثار علمیہ اور ان کے علوم وافکار کی اشاعت کے لیے کوئی جامع پروگرام بنانا چاہیے اور خاص طورپر ڈاکٹر صاحب سے دینی مدارس کے نصاب ونظام کی اصلاح اوربہتری کے حوالے سے جو کچھ کہا اور لکھا ہے، اسے وسیع پیمانے پر اہل مدارس تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ علما وطلبہ اس سے راہنمائی حاصل کر سکیں۔
ماہنامہ ’التجوید‘ کے مدیر ڈاکٹر قاری محمد طاہر نے ڈاکٹرغازی پر اپنے تفصیلی مضمون کے ایک منتخب حصہ سیمینار میں پڑھ کر سنایا۔ انھوں نے بتایا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنے پاس موبائل نہیں رکھتے تھے جس کی وجہ سے بعض اوقات ان سے رابطہ کرنے میں دقت پیش آتی تھی۔ ایک موقع پر انھوں نے ڈاکٹرصاحب سے پوچھاکہ وہ موبائل کیوں نہیں رکھتے تو انھوں نے کہا کہ اثمہما اکبر من نفعہما۔ قاری محمد طاہر نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کی حیات میں انھوں نے یہ واقعہ اپنے کالم میں لکھا اور ڈاکٹر صاحب کے علم وفضل کی تعریف میں کچھ کلمات لکھے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک خط میں انھیں لکھا کہ: ’’یقین جانیے کہ آپ کا ممدوح اتنی تعریفوں کا مستحق نہیں جتنی آپ کے مضمون میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ محض کسر نفسی یا تواضع نہیں، اظہار حقیقت ہے۔‘‘ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی طبیعت میں زہد کی خشکی نہیں تھی۔ شگفتہ مزاج تھے اور خط کا جواب دینا اس طرح ضروری خیال کرتے تھے جس طرح سلام کا جواب دینا۔ ان کے اندر تواضع اور انکساری بھی انتہا کی تھی۔
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے ڈاکٹر حافظ محمد سجاد نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ساتھ ڈاکٹر محمود احمد غازی کا ایک طویل تعلق رہا۔ ان کی پہلی ملاقات ڈاکٹر حمید اللہ سے ۱۹۷۳ء میں ہوئی اور پھر ان کی وفات تک یہ تعلق قائم رہا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی وفات کے موقع پر ان کی حیات وخدمات کے حوالے سے ادارۂ تحقیقات اسلامی اور علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی میں جو ریفرنس ہوئے، ان میں ڈاکٹر حمید اللہ کی حیات وخدمات پر سب سے عمدہ گفتگو ڈاکٹر صاحب نے ہی کی۔ علمی دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں ڈاکٹر حمید اللہ کی علمی خدمات کو متعارف کرانے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی کا بڑا کردار ہے۔ ڈاکٹر غازی ڈاکٹر حمید اللہ کو اس کے دور کے مجدد علوم سیرت کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے جتنی نئی جہات ڈاکٹر حمید اللہ نے متعارف کرائی ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کے خوشہ چین تھے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر غازی پر ڈاکٹر حمید اللہ کے علمی اعتماد کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی لکھی ہوئی تحریر میں کسی قسم کی کمی بیشی کیے جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر غازی کو انھوں نے اس کی اجازت دے رکھی تھی، چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے حضرت علی پر ایک مقالہ اردو دائرۂ معارف اسلامیہ کے لیے لکھا لیکن اس میں شاید کچھ ایسی باتیں تھیں کہ وہ اس میں نہ چھپ سکا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے وہ مقالہ ڈاکٹر غازی کو بھیجا اور ایک خط میں لکھا کہ ’’آپ کو اس میں ترمیم کی کامل آزادی ہے۔‘‘
ڈاکٹر حافظ محمد سجاد نے بتایا کہ ڈاکٹر غازی کے نام ڈاکٹر حمید اللہ کے ۱۲۶ خطوط ہیں جو انتہائی علمی، فکری ہیں اور ان میں عالم اسلام کے حالات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ان خطوط سے بہت سے علمی اور تحقیقی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ڈاکٹرحمید اللہ کی علمی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سے نئے موضوعات ان کے مطالعہ میں آتے رہتے تھے اور وہ فرانس میں بیٹھ کر عالم اسلام کے حالات پر کتنا غور وفکر کرتے رہتے تھے۔ اھوں نے بتایا کہ یہ خطوط ڈاکٹر غازی کی ہدایت پر کمپوز کر لیے گئے تھے اور ڈاکٹر صاحب ان خطوط کے حواشی تفصیل کے ساتھ خود لکھنا چاہتے تھے۔ میرے ساتھ آخری ملاقات میں انھوں نے فرمایا کہ اب میں پاکستان آ گیا ہوں، آپ کسی چھٹی کے دن آ جائیں تاکہ ہم اس کے حواشی لکھنا شروع کر سکیں، لیکن وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ خطوط تفصیلی حواشی کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مجلہ ’’معارف اسلامی‘‘ کی خصوصی اشاعت میں شامل کیے جائیں گے۔
ماہنامہ ’الشریعہ‘ گوجرانوالہ کے مدیر محمد عمار خان ناصر نے اپنی گفتگو میں ڈاکٹر محمود احمد غازی کے سلسلہ محاضرات کی اہم فکری خصوصیات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب قدیم وجدید علوم پر گہری نظر رکھتے تھے، دور جدید کے فکری وتہذیبی مزاج اور نفسیات سے پوری طرح باخبر تھے اور آج کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کو فکر وفلسفہ، تہذیب ومعاشرت، علم وتحقیق اور نظام وقانون کے دائروں میں جن مسائل کا سامنا ہے، وہ وسعت نظر، گہرائی اور بصیرت کے ساتھ ان کا تجزیہ کر سکتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا مقبول عام سلسلہ محاضرات ان کے غیر معمولی فہم وادراک اور علم وبصیرت کا ایک مظہر ہے۔ یہ محاضرات دور حاضر میں اسلامی دانش کا ایک بلند پایہ اظہار ہیں اور انھیں اردو زبان کے اعلیٰ اسلامی لٹریچر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔
پنجاب یونیورسٹی لاہور کے حافظ عبد الباسط نے اپنے مقالے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی کے ’’محاضرات حدیث‘‘ کے پس منظر اور اہمیت پر روشنی ڈالی اور مختلف خطبات کے مشمولات کا جائزہ پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ ان خطبات میں فتنہ انکار حدیث سے ایک مضبوط دفاع فراہم کیا گیا ہے۔ انھوں نے مختلف خطبات میں زیر بحث آنے والے اہم موضوعات اور اہم علمی نکات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان خطبات میں آسان اور عام فہم انداز میں مشکل اور پیچیدہ مباحث کو بیان کیا ہے اور علمی متانت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یادداشت اور مختصرنوٹس پر مبنی ہونے کی وجہ سے ان محاضرات میں علمی اعتبار سے کچھ خامیاں بھی رہ گئی ہیں۔ انھوں نے تجویز پیش کی کہ اگر کوئی صاحب علم اس پوری کتاب کا ایک اشاریہ مرتب کر دیں، معلومات کی توثیق کر دیں اور جو جگہیں قابل اصلاح ہیں، ان کی اصلاح کر دیں اور ہر بحث کے ممکنہ مصادر کا تذکرہ حاشیے میں کر دیں تو کتاب کی افادیت دوچند ہو جائے گی۔
ادارۂ تحقیقات اسلامی کے ریسرچ ایسوسی ایٹ ڈاکٹر محمد تنویر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ڈاکٹر غازی ان کے پی ایچ ڈی کے نگران تھے۔ بطور معلم ان میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو کسی کامیاب معلم میں ہوتی ہیں۔ وہ کئی پیچیدہ مسائل بآسانی طلبہ کو سمجھا دیتے تھے۔ کلاس میں مختلف تدریسی مناہج اختیار کرتے تھے۔ عام طور پر مدارس یا جامعات میں تدریس کا مرکز استاذ ہوتا ہے۔ غازی صاحب نے ہمارے لیے جو تدریسی منہج اختیار کیا، اس میں مرکز طلبہ ہوتے تھے۔ وہ کسی موضوع کے اہم مسائل ومباحث کا تعارف کروا کر مآخذ ومصادر کی طرف راہنمائی کر دیتے اور فرماتے کہ لائبریری میں ان مآخذ کا مطالعہ کر کے فلاں پہلو پر لکھیں اور لکھ کر تحریر مجھے دکھائیں۔ اس منہج کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کتابوں تک رسائی ہوئی اور قدیم مصادر اور جدید کتابوں سے اخذ واستفادہ کا ملکہ پیدا ہوا۔ جب کسی مسئلے پر بحث فرماتے تو یوں لگتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ بہت مرتب اورمربوط گفتگو ہوتی تھی۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر غازی کسی بھی مسئلے پر مختلف زاویوں سے نظر ڈالتے تھے۔ کہتے تھے کہ فقہا نے جو دلیل دی ہے، دیکھیے کہ مفسرین نے اس کو کیسے دیکھا ہے اور محدثین کا زاویہ نظر کیا ہے۔ پھر یہ کہ مختلف ادوار کے فقہا کا موقف کیا ہے۔ اس سے اس مسئلے کی پوری تصویر سامنے آ جاتی تھی۔ پھر وہ تفسیر، حدیث، لغت وغیرہ مختلف علوم کے حوالے سے راہنمائی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ترتیب زمانی سے علما کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سلف نے اس کو کیسے دیکھا، بعد میں آنے والوں نے اس میں کیاموقف اختیار کیا اور جدید دور کے اہل علم نے اس پر کیسے غور کیا ہے۔ کہتے تھے کہ جہاد کے بارے میں ہمارے بہت سے علما کا موقف اعتذاری رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں۔ آپ جم کر اسلام کے موقف کو پیش کیجیے۔ مثلاً جزیہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے یا نہیں، اس پر کلاس میں کافی بحث ہوتی رہی۔ پھر انھوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ جزیے کا مقارنہ زکوٰۃ کے ساتھ کریں کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے اور اس کے بدلے میں اسلامی ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کے مقابلے میں جزیے کی مقدار کیا ہے اور اس کے بدلے میں ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے اہم چیز ان کا تواضع تھا۔ وہ کسی بھی مسئلے پراپنا کوئی موقف پیش نہیں کرتے تھے۔ کبھی کوئی رائے ہوتی تو کہتے: قال صاحبکم۔
پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی نے اپنے خطاب میں بتایا کہ جس زمانے میں ہم اپنے والد مولانا مالک کاندھلوی کے ساتھ ٹنڈو الہ یار میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ والدہ میں نے اپنی والدہ سے بارہا سناہے۔ یہ ۷۰ء کے لگ بھگ کی بات ہے۔ غازی صاحب کے والد مرحوم میرے والد کے ماموں اور والدہ کے چچا تھے۔ ان کے والد کا خط میرے والد کے نام ایک پوسٹ کار ڈکی صورت میں آیا اور والدہ نے بھی پڑھا۔ انھوں نے مشورہ مانگا کہ محمود نے مجھ سے چھ کر میٹرک کا امتحان دے دیا ہے اور مجھے اب پتہ چلا ہے جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میری خواہش تو یہی ہے کہ وہ صر ف مدرسے میں پڑھے، لیکن اب چونکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے تو آپ مشورہ دیں کہ میں اسے انگریزی تعلیم آگے جاری رکھنے کی اجازت دوں یا نہیں۔ والدہ نے کہا کہ میں نے تمہارے والد سے کہا کہ انھیں مشورہ دیں کہ محمود کو آگے اس تعلیم کے جاری رکھنے کی اجازت دیں اور کبھی اس کو منع نہ کریں۔ چنانچہ مولانا مالک کاندھلوی نے انھیں خط لکھ کر مشورہ دیا کہ محمود کو اس سے نہ روکیں، مجھے بجا طو رپر یہ توقع ہے کہ آپ کی تربیت میں یہ بچہ جب آگے بڑھے گا تو کچھ بن کر نکلے گا اور مغربی تعلیم اس کے افکار اور نظریات کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔
ڈاکٹر سعد صدیقی نے کہا کہ میں نے جو تقویٰ ڈاکٹر محمود غازی کے اندر دیکھا، وہ تقویٰ بڑے بڑے علما میں بھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر سعد صدیقی نے بتایا کہ ایک موقع پر ہم نے قواعد فقہیہ پر لیکچر دینے کے لیے ڈاکٹر غازی کو پنجاب یونیورسٹی میں دعوت دی۔ اس موقع پر رات کو سونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پر میں نے انھیں التعلیق الصبیح کی پہلی جلد دے دی۔ صبح انھوں نے بتایا کہ میں نے یہ ساری کتاب پڑھ لی ہے۔ اگلے دن ڈاکٹر صاحب نے کسی قسم کے نوٹس کے بغیر قواعد فقہیہ کے خشک اور فنی موضوع پر مفصل گفتگو کی۔ انھوں نے کہا کہ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ کے کتاب العلم میں لکھا ہے کہ ملکہ علم پیدا ہونا بند ہو گیا ہے، لیکن کاش ابن خلدون زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ ملکہ علم آج بھی ہے اور ثبوت کے طور پر ڈاکٹر غازی صاحب کو ان کے سامنے پیش کرتا۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر غازی اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں۔
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامیہ کے استاذ ڈاکٹر محمد معین ہاشمی نے دینی مدارس کے بارے میں ڈاکٹر غازی کے خیالات کے حوالے سے ۔ انھوں نے کہا کہ وہ دینی مدارس کے بارے میں بہت فکرمند رہتے تھے اور ان سے کئی مرتبہ مدارس کے نصاب ونظام پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ مدارس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی فکر کی وضاحت میں ان کے کئی تحریری اقتباس پڑھ کر سنائے۔ امت مسلمہ فکری طو رپر حصوں میں بٹ گئی ہے۔ گزشتہ دو ڈھائی صدیوں میں مسلمانوں نے اپنی اس روایت کا دامن چھوڑ دیا ہے جو سلف نے قائم کی تھی۔ دینی مدارس اور مین اسٹریم نظام تعلیم دو الگ الگ رخوں پر چل نکلا۔ اب یہ دونوں طبقوں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے اورایک دوسرے کے پیش کیے ہوئے سوالات کا جواب دینے کے قابل نہیں۔ دور جدید کا آدمی جس فریکونسی پر بات کرتا ہے، عالم اس پر آپریٹ نہیں کرتا۔ ڈاکٹر غازی نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ علماء کرام جدید علوم کو اس حد تک پڑھ لیں کہ وہ جدید دور کی زبان اور محاورے میں اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکیں۔ دو متوازی جدولوں کے نقصانات پر گفتگو کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ یہ سیکولرازم کے غیر اسلامی تصور کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ سیکولرازم اسی کو کہتے ہیں کہ دین مسجد ومدرسہ تک محدود رہے اور دنیا کے عام معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔
مولانا محمد اسعد تھانوی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ڈاکٹر غازی کے والد محترم ایک سرکاری افسر تھے۔ پوری زندگی سرکاری کالونی میں رہے جہاں دائیں بائیں، ہر گھر کے بچے اسکول اور کالج میں جاتے تھے، اس کے باوجود انھوں نے اپنے بچوں کو اسکول یا کالج نہیں بھیجا، بلکہ مسجد کی چٹائی پر بٹھایا جہاں انھوں نے حفظ قرآن کیا۔ معروف طریقے پر علوم دینیہ حاصل کیے۔ پھر اللہ نے ان کو یہ ترقیاں عطا فرمائیں کہ وہ اسلامی یونی ورسٹی کے صدر بنے جہاں پوری دنیا کے اہل علم آ کر کام کرتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۲۰، ۲۲ سال پہلے مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی کی احکام القرآن کی تقریب جامعہ دار العلوم اسلامیہ لاہور میں منعقد ہوئی تو وہاں مولانا سلیم اللہ خان بھی تھے اور کافی اہل علم تھے۔ ڈاکٹر غازی اس وقت ایک نوجوان اور کم عمر آدمی تھے۔ وہاں انھوں نے جو تقریر کی، وہ میں نے پہلی مرتبہ سنی۔ میرے ساتھ مولانا سلیم اللہ خان بیٹھے تھے۔ جب جلسہ ختم ہوا تو مولانا سلیم اللہ نے حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ غازی صاحب نے علوم القران اور احکام القران کی پوری تاریخ ایسے پیش کر دی ہے جیسے کوئی کتاب ان کے سامنے کھلی ہو۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر غازی میں مولانا ادریس کاندھلوی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اگر وہ مدارس میں ہوتے تو ڈاکٹر غازی جیسا کوئی شیخ الحدیث پورے پاکستان میں نہ ہوتا۔
انھوں نے کہا کہ ان تمام عہدوں اور علمیت کے باوجود ان کی تواضع اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ رشتے میں جو بھی آدمی ان سے ایک دو سال بھی بڑا ہوتا، وہ اس کے جوتے اٹھا کر اس کے آگے رکھتے تھے۔ وہ مالی معاملات میں بے انتہا دیانت تھی۔ یونی ورسٹی کی گاڑی گھر کے کاموں کے استعمال میں نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ کراچی میں ، جب وہ وفاقی وزیر تھے تو میں ان سے ملنے گیا اور ان سے معاشیات، بینکنگ پر گفتگو شروع ہو گئی جو چار پانچ گھنٹے تک چلتی رہی۔ جب اختتام ہوا تو میں نے اندازہ کیا کہ اس آدمی کا تخصص معاشیات میں نہیں ہے، لیکن ان کو بین الاقوامی اور پاکستانی معاشیات کے متعلق جو معلومات تھیں، وہ ایک عام اکانومسٹ بھی نہیں رکھتا۔ ابھی ان کے انتقال سے پندرہ بیس روز پہلے ہمارے ایک بھتیجے کا انتقال ہو گیا۔ وہاں ڈاکٹر غازی نے قبرستان میں مولانا مشرف علی تھانوی سے، جو بارہ چودہ برس ان سے بڑے تھے، کہا کہ اگر میر اانتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ یہ انھوں نے وصیت کی اور پندرہ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے انھیں تلاوت قرآن سے بھی بڑا شغف عطا فرمایا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس موقع پر وہ اسلام آباد روانہ ہونے تک مسلسل تلاوت کرتے رہے۔
جامعہ ازہر میں شعبہ اردو کے استاذ الدکتور ابراہیم نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ ڈاکٹر غازی عالم اسلام کے ایک مایہ ناز محقق اور فقیہ تھے۔ وہ مترجم اقبال شیخ صاوی شعلان کی صحبت میں اس وقت رہے جب حکومت پاکستان نے انھیں غالباً ۱۹۶۷ء میں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ یہ عربی میں کلام اقبال بہترین منظوم ترجمہ ہے۔ صاوی شعلان کو ہیلن کیلر الشرق کہا جاتا تھا جو ایک اندھی، گونگی بہری خاتون تھی، لیکن نہایت بلند پایہ شاعرہ اور ادیبہ تھیں۔ صاوی شعلان بھی نابینا تھے اور انھیں کئی زبانوں پر عبور تھا جن میں اردو شامل نہیں تھی۔ انھیں اقبال کے کلام کی تفہیم کے لیے اردو دانوں کی ضرورت رہتی تھی اور محمد حسن اعظمی، عبد الباری انجم اور ڈاکٹر غلام محی الدین العربی نے ان کی معاونت کی۔ پاکستان میں قیام کے دوران غازی نے ان کی رفاقت اختیار کی اور جہاں وہ جانا چاہتے، غازی صاحب انھیں لے کر جاتے تھے۔ خاص طور پر علامہ اقبال کے مزارپر بیٹھ کر علامہ اقبال کے کلام پر گفتگو ہوتی تھی۔ غازی صاحب علامہ اقبال کے کلام کا نثری ترجمہ وتوضیح کرتے رہتے، تب جا کر شیخ صاوی علامہ کے کلام کو بہترین عربی جامہ پہناتے۔ اس سے ڈاکٹر غازی کے دونوں زبانوں پر عبور کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر غازی جیسے معتدل فکر اور متوازن شخصیت کے مالک علما اورمحققین کی موجودگی تمام عالم اسلام کے لیے باعث رحمت تھی اور ان کی وفات عالم اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔
رابطہ ادب اسلامی کے ڈاکٹر محمود الحسن عارف نے کہا کہ ڈاکٹر غازی ایک نابغہ روزگار ہستی تھی جن پر پاکستان کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ اللہ نے اس دور کے لیے جو رجال کار پیدا کیے، ان میں ڈاکٹر غازی کا نام بہت بلندی پر اللہ نے لکھا۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب رابطہ ادب کے بنیادی ارکان میں سے تھے اور جب یہاں شاخ قائم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کا نام مولانا رابع حسن ندوی نے بھیجا تھا اور ڈاکٹر صاحب رابطہ کے تمام پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے رہے۔ رابطہ مولانا ندوی کا تحفہ ہے جس کی شاخیں چودہ ممالک میں کام کر رہی ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ انھوں نے ’’ڈاکٹر محمود احمد غازی: مقاصد شریعہ کے شارح اور ترجمان‘‘ کے عنوان پر مقالہ لکھا ہے جو رابطہ الادب الاسلامی کے ترجمان ’’قافلہ ادب اسلامی‘‘ میں شائع ہوگا۔
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ڈاکٹر علی اصغر چشتی نے اپنے خطاب میں بتایا کہ میرا غازی صاحب کے ساتھ طویل عرصے تک قریبی تعلق رہا۔ ۸۲ء میں کیپ ٹاؤن میں قادیانیوں کے خلاف کیس کی کے سلسلیجو وفد گیا، اس میں ڈاکٹر غازی تشریف لے گئے تھے۔ اس پورے کیس کی تفصیلی رپورٹ ہفت روزہ ختم نبوت میں شائع ہوئی تھی۔ انھوں نے کہا کہ ۱۹۸۹ء میں جب غازی صاحب دعوہ اکیڈمی کے ڈی جی بنے تو انھوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تفسیر سے متعلق معلومات لوگوں کو درس قرآن اور خطبہ جمعہ سے کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں، اس لیے زیادہ ضرورت حدیث پر کورس تیار کرنے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر میں نے اس کورس کے یونٹ لکھنے شروع کیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے مسودے کا تفصیلی جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرتے اور کہتے تھے کہ یونٹ مکمل کرنے کے بعد یہ کسی مڈل یامیٹرک پاس عام آدمی کو پڑھائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ مسودہ اس کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حیدر آباد سے کچھ نو مسلم آئے اور لٹریچر کا تقاضاکیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ لٹریچر دیا اور پھر مجھے بلایا کہ ہمارے پاس عام فہم لٹریچر نہیں ہے۔ مولانا تھانوی کے لٹریچر کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر ہم نے عام فہم لٹریچر کا ایک منصوبہ تیار کیا۔
انھوں نے بتایا کہ علمی کاموں میں ڈاکٹر غازی کی دلچسپی عجیب وغریب تھی۔ ہر کام کو بہت باریکی میں جا کر دیکھتے اور پوچھتے تھے۔ سنٹرل ایشیا کے علما کا جب پہلا گروپ آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کراچی میں جا کر ان کا استقبال کریں اور ایک ہفتہ انھیں وہاں رکھ کر گھمائیں پھرائیں اور مدارس اور ادارے دکھائیں۔ دعوہ اکیڈمی کے ہرپروگرا م میں ڈاکٹر صاحب کی پوری دلچسپی ہوتی تھی۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب انتظامی معاملات میں بہت strict تھے، لیکن طلبہ کے ساتھ بے حد شفقت کا معاملہ کرتے تھے اور بہت نرم ہو جاتے تھے۔ انھوں نے کہاکہ یہ اسلامی یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں رہے، بلکہ اس یونیورسٹی کے وجود، اس کی تشکیل وترتیب میں ڈاکٹر غازی کا ذہن کارفرما ہے۔
ڈاکٹر محمد الغزالی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ڈاکٹر غازی کو بچپن سے ہی حصول علم کا بہت ذوق وشوق تھا اور وہ کبھی بچپن میں بھی کھیل کھلونے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اگر کبھی والد صاحب نے اصرار کیا کہ بتاؤ، تمھارے لیے کیا لاؤں تو وہ کوئی کتاب بتا دیتے تھے۔ کتاب سے بہت زیادہ دلچسپی اور علم کا حصول ان کی اولین priority تھی۔ کوئی ambition نہیں تھی، دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ انھوں نے بچپن سے کتابیں جمع کیں اور کیا کسی عورت کو زیور سے دلچسپی ہوگی اور کسی اور شخص کو اپنی پسندیدہ چیز سے جو انھیں کتاب سے تھی۔ انھوں نے بتایا کہ ڈاکٹر غازی نے خالص درسی دائرہ سے باہر دینی علوم اور عصری علوم پر عربی اور اردو کے ذخیرے سے بہت ابتدائی زندگی سے ہی استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں کسی صاحب علم کو دیکھا، وہ بس اس کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر غازی کو پچاس سال دیکھا ہے۔ وہ جس بات پرخوش ہوتے تھے، وہ یہی تھی کہ کوئی علمی کام ہو گیا، کوئی علمی نکتہ مل گیا، کوئی کتاب مل گئی، کوئی بات سمجھ میں آ گئی، کسی نے کوئی بات سمجھ لی، کوئی اچھا طالب علم ان کے پاس آکر اچھا کام کر گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم دین کا حصول ، اس کا فروغ، اسی کے لیے وہ جیے، اور اس کے سوا کسی چیز میں دلچسپی نہیں لی۔
جامعہ اشرفیہ کے نائب صدر مولانا فضل الرحیم نے اختتامی کلمات میں کہا کہ ڈاکٹر غازی سے میرا بہت تعلق رہا۔ ان کی وزارت کے دور میں ایک حج کی سعادت بھی ان کی معیت میں ہوئی۔ جامعہ اشرفیہ میں عصری تعلیم کا آغاز کرنے میں میرے ساتھ ان کی تین چار محفلیں ہوئیں او رجب تک مجھ سے اس کام کا آغا زنہیں کروایا، مجھے چھوڑا نہیں۔ کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر مجھ سے اس کام کے فوائد بیان کرتے رہے اور الحمد للہ اس وقت جامعہ اشرفیہ کے کم وبیش پچاس کے قریب فضلا پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس میرا ایک عزیز سفارشی رقعہ لینے کے لیے گیا تو انھوں نے اپنے پی اے سے کہا کہ ان کو ایک سفارشی خط لکھ دیں۔ اس نے الماری سے ایک کاغذ نکالا اور اس پر سفارشی رقعہ لکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ دعوہ اکیڈمی کے لیٹر پیڈ پر کیوں نہیں لکھا تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ جہاں میرا ذاتی کام ہو، وہاں دعوہ اکیڈمی کا لیٹر پیڈ بھی استعمال نہ کیا جائے۔ میرے عزیز نے بتایا کہ پھر انھوں نے اس پر دستخط بھی اپنے ذاتی قلم سے کیے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک عزیز کو داخلے کے لیے بھیجا تو انھوں نے کہا کہ میں داخلہ دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ اس ملک کو سو تقی عثمانی کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ تم تقی عثمانی بنو گے۔ انھوں نے کہا کہ ڈاکٹر غازی جاتے ہوئے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ اپنی فکر کرو۔ اپنی آخرت کا فکر کرو۔ انھوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر غزالی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نگرانی میں ڈاکٹر غازی کی ایک مفصل سوانح مرتب کروائیں۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین پیغام ہوگا۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ ورلڈ اسلامک فورم کے زیر اہتمام تعزیتی نشست
ادارہ
پاکستان کے بین الاقوامی اسکالر، ممتاز مفکر وعالم دین جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی کے انتقال پر ورلڈ اسلامک فورم، برطانیہ کے زیراہتمام ایک تعزیتی اجلاس ایسٹ لندن کے معروف ادارہ ’’ابراہیم کالج ‘‘میں مولانا محمد عیسیٰ منصوری چیئرمین ورلڈ اسلامک فورم کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں لندن کے علاوہ برطانیہ کے مختلف شہروں سے علماے کرام، اسکالرز اور تنظیموں کے سربراہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
اجلاس کا آغاز مولانا محمد الیاس کی تلاوت قرآن سے ہوا۔ اس کے بعد فورم کے نائب صدر اور السلامۃ کمپیوٹر سنٹر کے ڈائریکٹر جناب مفتی برکت اللہ صاحب نے کہا کہ گذشتہ ۱۸ سال سے ڈاکٹر صاحب کا فورم کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ فورم کے طرف سے جب بھی انہیں مدعو کیا گیا، وہ برطانیہ تشریف لائے۔ تہذیبوں کے تصادم کے اس دور میں ڈاکٹر صاحب کے علم وفکر سے پورا عالم اسلام رہنمائی حاصل کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے انتقال سے عالم اسلام کی علمی و فکری کاوشوں کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔
جامعۃ الہدیٰ نوٹنگھم کے پرنسپل مولانا رضاء الحق نے کہا کہ ڈاکٹر محمودا حمد غازی کی وفات پر یہ مقولہ صادق آتا ہے کہ ’’عالِم کی موت، عالَم کی موت‘‘ ہے۔ وہ متعدد بار جامعہ الہدیٰ میں تشریف لائے اور برطانیہ کی مسلمان بچیوں کے لیے دینی و عصری تعلیم کا نہایت موثر نصاب تعلیم مرتب کر نے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے بعد علمی، فکری اور تعلیمی میدان میں کوئی متبادل نظر نہیں آتا۔
مفتی عبدالمنتقم سلہٹی نے کہا: ڈاکٹر صاحب کا علمی کام مشعل راہ ہے۔ ان کی وزارت کے زمانہ میں ، میں وفد لے کر اسلام آباد ملنے گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود مجھ جیسے معمولی طالب علم کے لیے فقہ اسلامی کے موضوع پر کئی گھنٹے گفتگو فرمائی۔ آپ کو فقہ اسلامی اور اسلامی اقتصادیات پر بے پناہ بصیرت حاصل تھی۔
جماعت اسلامی کے رہنما جناب رضوان فلاحی نے کہا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا ایک اہم کام دینی نصاب تعلیم کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صرف عالم دین نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی شخصیت اسلامی علوم وفکر میں مرجعیت کا مقام رکھتی تھی۔
ابراہیم کالج کے پرنسپل مولانا مشفق الدین نے انگریزی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا میں علم حاصل کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ صرف مذہبی تعلیم سیکھ کر اور عصری علوم وتقاضوں سے بے بہرہ رہ کر کنویں کی مینڈک کی طرح محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عصری علوم سیکھ کر دین ومذہبی علوم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم بلکہ نایاب ہیں جو دینی و عصری علوم میں گہری بصیرت حاصل کر کے ملک و ملت کو اپنے علوم و فکر سے مالا مال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو مستفید کیا۔ ہمارے ابراہیم کالج کا تعلیمی خاکہ بنانے میں ڈاکٹر صاحب کا بنیادی کردار ہے۔
روزنامہ جنگ (لندن) کے سابق ایڈیٹر جناب ظہور نیازی نے کہا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی شخصیت اتنی ہمہ گیر تھی کہ تمام مکاتب فکر اور علوم کے بے شمار شعبوں کے لوگ آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی اعتراف پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میرے ہاتھ میں قادنیوں کی ویب سائٹ سے نکالا ہوا ایک پیپر ہے جس پر لکھا ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے سولہ سال کی عمر میں دینی علوم سے سند فراغت حاصل کر کے ۱۷؍ سال کی عمر میں تدریس شروع کر د ی تھی۔ بقول قادیانیوں کے ڈاکٹر صاحب ہی نے جنرل ضیاء الحق کے ذریعے منکرین ختم نبوت کے لیے قانون سازی کروائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب علم حقیقی کے وارث تھے۔ ان کو دیکھ کر امام غزالی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ مجھے ڈاکٹرصاحب کے محاضرات نے بہت متاثر کیا۔ یہ محاضرات ہر تعلیم یافتہ شخص کے پڑھنے کے لائق ہیں۔ ضرورت ہے کہ ورلڈ اسلامک فورم ڈاکٹر صاحب کے فکر و نظر کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔
جمعیۃ علماء برطانیہ کے صدر مولانا ڈاکٹر اخترالزمان غوری نے کہا یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ ہر دور میں ایسے رجال کار پیدا ہوتے رہے جو اسلام کو عصری فہم اور زمانہ کی ذہنی سطح کے مطابق پیش کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کام اور فکر کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ ورلڈاسلامک فورم ڈاکٹر صاحب کی کتابوں خاص طور پر محاضرات کا انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کرنے کی طرف توجہ مبذول کرے۔ انھوں نے کہا کہ مولانا عیسیٰ منصوری نے یہ تعزیتی اجلاس منعقد کر کے پورے اہل برطانیہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے اور ہم پر احسان کیا ہے۔
جمعیۃ اہل حدیث برطانیہ کے صدر ڈاکٹر صہیب حسن صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایک عبقری شخصیت تھی۔ آپ نے پوری زندگی بغیر مسلکی تعصب کے علمی ودینی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے والد مرحوم سے بھی اجازت حدیث حاصل کی تھی۔ آپ نے پاکستان میں دعوۃ اکیڈمی اور شریعۃاکیڈمی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بیش بہا خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی وزارت سے دینی مدارس کی حمایت میں استعفا دے دیا اور سود کے مسئلہ پر سپریم کورٹ میں مدلل تقریر کر کے صحیح فیصلہ کروایا۔
مولانا محمد عیسیٰ منصوری نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی شخصیت نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیے علوم اسلامی اور فکر اسلامی کا سرچشمہ تھی۔ آپ کی ہستی بین الاقوامی کانفرنسوں و مجالس اور اعلیٰ سطح پر اسلام او ر جمہور اہل علم کی ترجمانی کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مملکت پاکستان کے آئینی وقانونی مسائل میں بھرپور رہنمائی دی۔ آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع بلکہ ہمہ گیر تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا فورم ہو یا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی دعوۃ اکیڈمی وشریعہ اکیڈمی کے ذریعے دنیا بھر میں اشاعت علوم اسلامی اور اسکالرز تیار کرنے کا مسئلہ، سپریم کورٹ میں سود کے متعلق تاریخی فیصلے کا معاملہ ہو یا اسلامی اقتصادیات وبینکنگ کا مسئلہ، قادیانیت کے متعلق متفقہ موقف کی اشاعت کی بات ہو یا اس سلسلے میں ہونے والی قانون سازی کا مسئلہ، ڈاکٹر محمود احمد غازی کی جہد مسلسل، تگ ودو اور ماہرانہ رائے کا ہر جگہ بڑا دخل رہا ہے۔ آپ نے ساؤتھ افریقہ کی غیر مسلم عدالت میں قادیانیوں کے خلاف تاریخی مقدمہ میں ملت اسلامیہ کے موقف کو غیر مسلم عدالت میں سرخرو کر کے اسے پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کی عدالتوں کے لیے ایک نظیر و مثال بنا دیا۔ اسی طرح پرویز مشرف کے دور میں جب امریکی ایما پر مدارس کے خلاف یلغار ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے خداداد صلاحیت و بصیرت اور حکمت عملی سے اسے ناکام کر دیا جو پاکستان کے دینی مدارس پر ڈاکٹر صاحب کا عظیم احسان ہے۔
مولانا منصوری نے کہ عالم اسلام میں ڈاکٹر حمیداللہ کے بعد ڈاکٹر غازی ایک ایسی شخصیت تھے جو اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور فارسی سمیت متعدد زبانوں پر اعلیٰ درجہ کی تصنیف وخطابت کی اہلیت وملکہ رکھتے تھے۔ ان زبانوں میں ان کی تیس کے قریب تصانیف اہل علم اورنسل نو کے لیے بیش بہا تحفہ ہیں۔ آپ کے محاضرات جو قرآن، حدیث، سیرت، فقہ ، شریعت اور تجارت ومعیشت پر ہیں، پورے اسلامی کتب خانہ میں بے مثل ہیں۔ برصغیر میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی تھی جن کی عالمی حالات پر گہری نظر تھی اوراس تہذیبی تصادم کے دور میں مغرب کے صلیبی صیہونی گٹھ جوڑ سے عالم اسلام کو جو تہذیبی وفکری چیلنجز اور خطرات در پیش ہیں، ڈاکٹر صاحب علمی وفکری سطح پر اس کا موثر جواب دے رہے تھے۔ آپ کی وفات نظریاتی فکری کام کرنے والوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ ہم ایک فکری رہنما سے محروم ہو گئے۔ آپ نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے علاوہ ملائیشیا اور قطر کی یونیورسٹیوں میں بھی اسلامی فکر وفلسفہ کی جوت جگائی۔ ایک عرصہ سے ڈاکٹر صاحب کے فکروفلسفہ کو عام کرنے میں ورلڈ اسلامک فورم، مولانا زاہدالراشدی اور ان کا ادارہ الشریعہ اکادمی کا خاص رول رہا ہے۔ مولانا منصوری نے اعلان کیا کہ ورلڈ اسلامک فورم ان کے محاضرات کو انگریزی میں ترجمہ کروا کر شائع کرے گا، جبکہ فورم ہی کی وساطت سے برطانیہ میں ڈاکٹر صاحب کی راہنمائی میں جاری کیے جانے والے ’’ہوم اسٹڈی کورس‘‘ سے دس ہزار کے قریب طلبہ وطالبات استفادہ کر چکے ہیں ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ ۔ رسائل و جرائد کے تعزیتی شذرے
ادارہ
(۱)
حضرت مولانا غلام رسول خاموش اور حضرت مولانا مرغوب الرحمن قاسمی کی وفات سے پہلے ملت اسلامیہ، خصوصاً برصغیر کے دینی وعلمی حلقوں کو ایک اور حادثہ سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ یہ تھا ڈاکٹر محمود احمد غازی کے انتقال پرملال کاحادثہ جو ۲۶؍ ستمبر ۲۰۱۰ء کو پیش آیا۔ ڈاکٹر صاحب اس دور کے ان ممتاز اہل علم ودانش میں تھے جو پاکستان اور عالم اسلام میں جاری اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں اسلام کے ایک وفادار اور جاں باز سپاہی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ویسے تو مختلف اسلامی علوم میں ان کو عبور حاصل تھا، مگر فقہ وقانون میں ان کو زبردست مہارت حاصل تھی اور قدیم علمی سرمایے کو جدید اسلوب میں پیش کرنے میں ان کو غیر معمولی ملکہ حاصل تھا۔ وہ پاکستان کے فیڈرل شریعہ عدالت کے جج بھی تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم دینی مدارس میں ہوئی تھی۔ بعد میں انھوں نے یونیورسٹیوں کی ڈگریاں بھی حاصل کیں اور راقم کے اندازے کے مطابق قدیم وجدید کے درمیان توازن قائم رکھنے میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے اور اہل نظر جانتے ہیں کہ اس کا کہنا تو آسان ہے، مگر ہر جزئیہ اور ہر فکر اور ہر تعبیر میں یہ بہت ہی دشوار کام ہے۔
یہ راقم مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کا شکر گزار ہے کہ انھوں نے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی شخصیت کے بارے میں اپنے تاثرات پر مشتمل مفصل مضمون ’الفرقان‘ میں اشاعت کے لیے ارسال کیا جو اس شمارے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم ڈاکٹر غازی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی مساعی کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے تمام پس ماندگان اورمتعلقین ومحبین کو صبر واجر عطا فرمائے۔
گزشتہ سال کے آخری دنوں میں مذکورہ بالا تینوں شخصیتوں کے اٹھ جانے سے بلاشبہ بہت بڑی کمی ہوئی ہے۔ اب ہم سب کی ذمے داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے اسلاف سے خدمت دین کی اس امانت کی وراثت قبول کریں اور اسی اخلاص، استغنا اور عزم وحکمت کے ساتھ کام کو جاری رکھیں۔ محترم قارئین سے ان تینوں حضرات کے لیے دعاؤں اورمسنون طریقے پر ایصال ثواب کے اہتمام کی بھی گزارش ہے۔
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِیْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّکَ رَؤُوْفٌ رَّحِیْمٌ۔
مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی
(ماہنامہ الفرقان، لکھنو)
( ۲ )
احقر ۱۶؍ شوال المکرم کوچنیوٹ جار ہا تھا۔ راستے میں مخدوم و مکرم حضرت مولانا مشرف علی تھانوی مدظلہم نے فون پر اطلاع دی کہ جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ ۲ بجے اسلام آباد میں ان کا جنازہ ہوگا۔ اچانک ملنے والی اس خبر سے بہت افسوس ہوا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم باقاعدہ درس نظامی اورعصری تعلیم کے فاضل تھے۔ ان کے والد مرحو م کا حضرت حکیم الامت تھانوی ؒ سے خاص تعلق تھا، اس لیے ان کی تربیت اور نشوونما بڑے دینی اور علمی ماحول میں ہو ئی جس کا اثر ان کی زندگی پر آخر دم تک قائم رہا۔ عصر جدید کے چیلنج اور دورحاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر دین کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ ہمیشہ فکر مند رہے اور انہوں نے ہمیشہ اہل علم کو بھی اس طرف متوجہ کیا۔ اپنی علمی، دینی، فکری صلاحیتوں کی بنیاد پر انہوں نے چیلنجوں کا خوب مقابلہ کیا اور اس محاذ پر اہل علم اور دین کی نمائندگی کی۔ مرحوم بڑے فاضل اور قابل جوہر تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سا ذخیرہ چھوڑا ہے جو اہل علم کے لیے یقیناًقابل قدر ہے۔ ان کے بعض افکار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک ان کے اخلاص اور درد دل کے ساتھ عالم اسلام کے لیے گرانقدر خدمات کا تعلق ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور پس ماندگان کو صبر واجر سے نوازیں۔
احقر کو ان سے مستفید ہونے کا موقع نہیں ملا، لیکن جو ملاقاتیں ہوئیں، ان کا گہرا نقش اب تک احقر کے قلب پر موجود ہے۔ دارالعلوم الاسلامیہ لاہور میں ایک دو مرتبہ ان سے ملاقات ومجلس ہوئی۔ احکام القرآن کی تقریب میں ان کا خطاب ذی شان بھی سنا۔ اس میں انہوں نے جب آیت قرآنی: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّہْلِکَ قَرْیَۃً أَمَرْنَا مُتْرَفِیْہَا فَفَسَقُوا فِیْہَا فَحَقَّ عَلَیْْہَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاہَا تَدْمِیْراً (۱۷:۱۶) میں ’’أَمَرْنَا‘‘ کی وضاحت کی تو سامعین بڑے ہی محظوظ ہوئے۔ بعد میں حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے اپنے خطاب میں ان کی بڑی تعریف فرمائی۔
حضرت والد صاحب ؒ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے بڑے متاثر ہوئے۔ حضرت نے ان سے امام جصاص کے تحریر فرمودہ مقدمہ احکام القرآن کا ذکر فرمایا تو انہوں نے اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی میں تلاش کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت والد صاحب سے تاثر ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بڑے اصرار سے حضرت کو راضی کر کے اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنایا اور پھر ان کی وفات پر بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ چند سال قبل احقر ان کی دعوت پر اسلام آباد میں منعقدہ سہ روزہ بین المذاہب کانفرنس میں حاضر ہوا اور ان کا فاضلانہ خطاب بھی سنا۔
ایک مرتبہ جنرل پرویز مشرف کی دعوت پر اسلام آباد میں حضرات علماء کرام تشریف لے گئے۔ احقر بھی حاضر ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ وہ خود بھی صاحب فضل وکمال اور عالم وفاضل تھے، اس لیے اہل علم کے بے حد قدر دان تھے۔ ان کے جانے سے علمی اور تحقیقی دنیا میں ایک نیا خلا پید اہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما ویں اور اس خلا کو پورا کرنے کی بعد کے حضرات کو توفیق عطا فرمائیں۔
مولانا مفتی عبد القدوس ترمذی
(ماہنامہ الحقانیہ، ساہیوال)
( ۳ )
وفاقی شرعی عدالت کے جج، مجمع الاسلامی کے ممبر، قومی سلامتی کونسل واسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، شریعت اپیلٹ کورٹ کے سابق جج اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے سابق صدر ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ۱۶؍ شوال المکرم ۱۴۳۱ء /۲۶؍ ستمبر ۲۰۱۰ء کو حرکت قلب بند ہونے سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ؒ حافظ قرآن، عالم دین، مشہور اسکالر، دینی ودنیاوی علوم کے جامع، اسلامی اصول وضوابط پر مطلع اور درجنوں کتابوں کے مولف تھے۔
سن ولادت ۱۸؍ ستمبر ۱۹۵۰ء ہے۔ مقام ولادت کراچی ہے۔ والد محترم کا نام محمد احمد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حفظ وناظرہ کی تعلیم مدرسہ اشرفیہ جیکب لائن کراچی میں قاری حافظ نذیر احمد متوفی ۱۲؍ ذوالحجہ ۱۴۱۰ھ/۸؍ جولائی ۱۹۹۰ء سے حاصل کی۔ اس کے بعد جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کراچی میں داخلہ لیا اور درس نظامی کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ غازی صاحب نے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں داخلہ لیااور وہیں سے فراغت پائی اور بانی جامعہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ؒ سے بھی استفادہ کیا جب کہ غازی صاحب ؒ نے ۱۹۷۲ء میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ چونکہ غازی صاحب دینی ودنیاوی علوم کے جامع، دینی مدارس وجامعات اوراسکول وکالجز کے اسرار ورموز پر مطلع تھے اور ساتھ ملک وملت کے بھی خیر خواہ تھے، اس لیے غازی صاحب ملک کے درجنوں اداروں کے اہم عہدوں پر فائز رہے اور قومی وملی خدمات سرانجام دیں۔
غازی صاحبؒ نے ۲۰۰۲ء سے ۲۰۰۴ء تک بطور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور فرائض سر انجام دیے ۔ ۲۰۰۴ء سے ۲۰۰۶ء تک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر رہے جب کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور نواز شریف کے دورمیں شریعت اپیلٹ کورٹ کے جج رہے۔ غازی صاحب عرب ممالک کی جدید ڈکشنری مجمع الاسلامی [؟] کے تاحیات ممبر تھے اور یہ واحد مذہبی اسکالر تھے جو غیر عرب تھے۔ ۲۶؍ مارچ ۲۰۱۰ء کو غازی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے اور آخری دم تک اس خدمت میں مصروف رہے۔
غازی صاحب کی پوری کوشش تھی کہ دینی مدارس کے علماء کرام کو عصری تعلیم سے روشناس کرائیں اور دینی مدارس کے نظام تعلیم میں اس طرح ردو بدل کیا جائے کہ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ عصری علوم کے بھی ماہر ہوں اور غازی صاحب کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ تنقیدی مضامین پر چراغ پا ہونے کی بجائے انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ان مضامین کو پڑھتے اور خیرمقدم بھی کرتے تھے۔
غازی صاحب کا ایک مضمون ہفت روزہ تکبیر کراچی، شمارہ ۵؍فروری ۲۰۰۴ء میں شائع ہوا تھا اور راقم نے اس مضمون کے بعض اقتباسات پر اپنا اظہار خیال کیا تھا ۔ یہ تنقیدی اظہار خیال جب ماہنامہ حق نوائے احتشام کراچی، شمارہ صفرالمظفر ۱۴۲۵ھ /اپریل ۲۰۰۴ء میں شائع ہوا تو غازی صاحب نے فون پر رابطہ فرمایا اور برا ماننے کے بجائے حوصلہ افزائی فرمائی۔ غازی صاحب کی ایک تالیف بنام ’’مسلمانوں کا دینی وعصری نظام تعلیم‘‘ ہے۔ صفحات ۲۵۶ ہیں۔ اس کتاب پر تبصرہ ماہنامہ حق نوائے احتشام شمارہ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ /مارچ ۲۰۱۰ء میں شائع ہوا۔ اس کتاب کے بعض اقتباسات پر بھی تنقید ہے، لیکن غازی صاحب نے حسب معمول فون پر سلام کلام کیا اور انتہائی مودبانہ ومشفقانہ انداز میں گفتگو فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ غازی صاحب بے حد وسیع الظرف اور تحقیقی وعلمی شخص تھے۔
رجب المرجب ۱۴۲۶ھ /اگست ۲۰۰۵ء کو ہمارے ادارے سے ’’ متاع احتشام الحق‘‘ کے نام سے سات سو صفحات پر مشتمل ایک کتاب منظر عام پر آئی۔ حسب معمول ایک نسخہ غازی صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا گیا۔ نسخہ ملنے کے بعد غازی صاحب نے جو خط بھیجا، وہ یہ ہے:
برادر مکرم ومحترم جناب مولانا حافظ محمد صدیق ارکانی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا پہلا گرامی نامہ چند روز قبل موصول ہوا۔ اس سے خوشی ہوئی کہ آپ اپنے رسالہ کا خصوصی شمارہ شائع کر رہے ہیں۔ ابھی اس کاجواب دینے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ خصوصی شمارہ کی ایک کاپی بھی موصول ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔ میری طرف سے مولانا تنویر الحق صاحب کی خدمت میں شکریہ کے جذبات پہنچا دیجیے۔ رسالہ کے مضامین اور تصاویر نے چالیس سالہ پرانی یادیں تازہ کر دیں۔
والسلام ڈاکٹر محمود احمد غازی
رئیس الجامعۃ الاسلامیۃ العالمیۃ
اسلام آباد ، پاکستان
مورخہ : ۱۸؍ اگست ۲۰۰۵ء
غازی صاحب کی متعدد تالیفات ہیں جن میں محاضرات، قانون بین الممالک، اسلام اور مغرب تعلقات، مسلمانوں کا دینی وعصری نظام تعلیم، اسلامی بنکاری: ایک تعارف، آداب القاضی، قرآن مجید: ایک تعارف معروف ہیں۔ محاضرات نامی کتاب چھ جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد ۱۲ خطاب کامجموعہ ہے۔
غازی صاحبؒ کو سات زبانوں پر عبور تھا اور پس ماندگان میں ایک بیوہ اور پانچ بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غازی صاحبؒ کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کرے۔
مولانا محمد صدیق اراکانی
(ماہنامہ حق نوائے احتشام، کراچی)
( ۴ )
آسمان علم وتحقیق کا ایک درخشندہ ستارہ گزشتہ دنوں اچانک بحر فنا میں ڈوب گیا۔ مسند علم وعرفان کی ایک ایسی شمع یکایک بادِفنا کی ستم ظریفی سے ہمیشہ کے لیے بجھ گئی ہے جس کی تلاش میں کہکشائیں بھی جلائی جائیں توبھی اس کی تلافی ممکن نہیں۔
اب انہیں ڈھونڈچراغ رخ زیبا لے کر
جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان کے لیے بہت بڑا علمی سرمایہ تھے۔ پاکستان اور برصغیر میں آپ کے پائے کے قابل اور فاضل افراد گنے چنے ہی نہیں بلکہ ایک دو افراد ہی ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب کی علمی، تحقیقی، فنی، ادبی اور تعلیمی خدمات اتنی زیادہ اور وسیع ہیں کہ ان کااحاطہ ایک طالب علم کے بس کی بات نہیں۔ یقیناًڈاکٹر صاحب اس وقت علم وتحقیق کے میدان میں حضرت مولانا مفتی محمدتقی عثمانی مدظلہ کے بعد بہت نمایاں مقام پر فائز تھے۔ آپ کچھ عرصے میں اداروں اور اکیڈمیوں کا کام کر گئے۔ طبیعت میں تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کم گوئی اور خاموشی آپ کی نمایاں خصوصیت تھیں اور علمی نخوت وتکبر سے بھی آپ کوسوں دور تھے۔
آپ اگرچہ جدید علوم وفنون میں ممتاز تھے اور آپ پر عصر حاضر کے رنگ کا عکس بھی کافی گہرا پڑ چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم وفنون پر بھی آپ کی دسترس کسی شیخ اور کسی دینی وعلمی مستند ترین شخصیت سے کم نہیں تھی۔ آپ ایک ایسے دریا کی مانند تھے جس میں قدیم وجدید دونوں علوم پانی کی مانند جمع تھے اور ایسا علمی خزانہ تھے جوجمع ہونے کی بجائے خود کوخرچ کرنے پر ترجیح دیتے تھے۔ دراصل آپ کی بنیاد ہی اسلامی مدرسے سے بنی تھی اور علوم شرعیہ میں کمال بھی آپ نے کراچی کے ایک بڑے علمی ادارے سے حاصل کیاتھا۔ پھربعدمیں اپنی جدت پسند اور خدا داد صلاحیتوں سے آپ ترقی کرتے کرتے علم وعرفان کے بلند ترین مسانید پر فائز ہو گئے۔ آپ کے قیمتی قلم سے کئی علمی اور تحقیقی ضخیم کتابیں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئیں اور آپ کے پرمغز علمی مقالات، تقاریر،علمی سیمیناروں کی جان ہوا کرتے تھے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے صدر اور فیصل مسجد کی خطابت بھی آپ نے کئی برس تک کی۔ اس کے علاوہ دیگر کئی علمی وتحقیقی اداروں کے بھی آپ رئیس رہے اور کافی عرصہ وفاقی وزیر مذہبی امور پاکستان بھی آپ رہے۔ اس وقت آپ وفاقی شرعی عدالت کے معزز جج کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے رہے تھے۔
پاکستان جو پہلے ہی مفلسی اور غربت کے ہاتھوں گھر اہواہے اوراس کا تعلیمی اور علمی سرمایہ بھی آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، اب ڈاکٹر صاحب جیسی قیمتی شخصیت کے اٹھ جانے کے باعث توعلمی وتحقیقی مفلسی بھی پاکستان کے حصے میں آ گئی ہے۔ تعلیمی انحطاط روز بروز بڑھتا چلا جا رہاہے۔ درسگاہیں ویران، حقیقی طالب علم ناپید اور اساتذہ وپروفیسر علم وادب سے بے خبر۔ ایسے ماحول اور ایسے ملک میںآپ جیسے عظیم معلم، استاد،مفکر اور محقق کا بچھڑ جانا مزید گہرے صدمے کا باعث ہے۔ اب تو پور ے ملک میں لے دے کر چند ہی نابغے باقی ہیں۔ اللہ انہیں اپنے حفظ وامان میں رکھے اور ڈاکٹر صاحب کے مقامات اعلیٰ علیین میں مقرر فرمائے اور ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
مولانا راشد الحق حقانی
(ماہنامہ الحق،ا کوڑہ خٹک)
( ۵ )
ملک کی بے حد قابل احترام اور وقیع علمی شخصیت، جسٹس وفاقی شرعی عدالت اورسابق صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ وطن عزیز کی ان ہستیوں میں شامل تھے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان تھے، اس کے علمی مقام ومرتبہ کی شناخت تھے۔ وہ دینی اور جدید وقدیم علوم کے ایسے عظیم اسکالر تھے جن پر کوئی بھی قوم فخر کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے اعزازات سے نوازا تھا۔ وہ کئی ایک قومی وملی اور علمی وتدریسی مناصب پر فائز رہے اور ہرجگہ سزاوار احترام ٹھہرے۔ وہ تحریر وتقریر دونوں ہی میدانوں کے شہسوار تھے۔ ان کی تصنیف کردہ کتب علم کا ایسا خزینہ ہیں جن سے آنے والی نسلیں مدت مدیر تک استفادہ کرتی رہیں گی۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی کے اچانک سانحہ ارتحال سے اسلامی، علمی اور قومی وملی حلقوں میں بہت بڑا خلا پیدگیا ہے۔ ایسا خلا جسے قدرت الٰہیہ فوری طور پر پرکر دے تو کوئی بعیدنہیں۔ وما ذلک علی اللہ ببعید۔ بظاہر ایسا ممکن نظر نہیںآتا۔ ہم قحط الرجال کے جس بدترین دور سے گزر رہے ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی کی رحلت نے اس کی شدت میں کچھ اور اضافہ کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت تامہ کے لیے دست بدعاہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی بشری لغزشوں سے درگزر فرماتے ہوئے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہیں انبیا واتقیا اور صلحا کی معیت نصیب ہو اور ان کی اخروی زندگی ان کی اس حیات مستعار سے کہیں زیادہ قابل رشک ٹھہرے۔ آمین۔ ہم ان کے سبھی لواحقین بالخصوص ان کے برادر گرامی جناب ڈاکٹر محمد الغزالی سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے لیے صبرجمیل کے طالب ہیں۔
ڈاکٹر زاہد اشرف
(ماہنامہ المنبر، فیصل آباد )
( ۶ )
۲۶؍ ستمبر کو معروف اسکالر، علمی وادبی اور تحقیقی کاز کے حوالے سے جدید وقدیم علوم کے متبحر عالم دین، اسلامی یونیورسٹی کے سابق صدر، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور وسابق خطیب فیصل مسجد، وفاقی شرعی عدالت کے جج ، ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ بھی حرکت قلب بند ہونے سے راہی جنت ہو گئے ہیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی ؒ ایک وسیع المطالعہ شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کیا اور بھرپور استقامت اور عزیمت کے ساتھ اس مقصود کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی بسر کر دی۔ وہ جدید اور قدیم علوم پر گہری نظر رکھتے اور اپنی بات بڑے سلیقے سے کہنے کا ہنر جانتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت کم لوگ اتنے شستہ اور اتنے اعلیٰ اسلوب میں اپنا مدعا بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ میری سب سے پہلی ملاقات مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب کے مدرسہ کے سالانہ جلسہ دستاربندی میں ہوئی۔ میں جلسہ گاہ میں پہنچا تو ایک عالمانہ، فاضلانہ خطاب شروع تھا۔ خطیب کی اردو سے علم و ادب چھلکتا تھا،جگہ جگہ قرآن کی آیات سے استدلال، احادیث سے استشہاد اور متنبی اور حماسہ کے عربی اشعار بھی بطور دلیل پیش کیے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، خطیب کون ہیں؟ بتایاگیا کہ مرکزی وزیر جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں۔ اسی شام دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے اور چند لمحوں میں موصوف بے تکلف ہو گئے ۔ مجھے اس رو ز اس پر اور زیادہ خوشی ہوئی کہ موصوف میری اکثر کتابوں کو جانتے بھی تھے، مطالعہ بھی کیا تھا اور انہیں میری بعض جدید کتب کی طلب بھی تھی۔ انہوں نے کئی بار جامعہ ابوہریرہ آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ماہنامہ القاسم کوشوق سے دیکھتے بلکہ فرماتے کہ میں اس کے انتظار میں رہتا ہوں۔
گزشتہ کئی سالوں سے ان کے علمی افادات بھی منظر عام پر آنے لگے۔ قرآنیات ، احادیث اور فقہ پر ان کے علمی لیکچرز ان کے وسیع و عمیق مطالعہ اور علم وتحقیق کامظہر ہیں۔ ان کے خطبات ،محاضرات قرآن، محاضرات حدیث، محاضرات سیرت سے دین اور مطالعاتی حلقوں میں ان کا علمی مقام بہت بڑھ گیاتھا۔ بلاشبہ وہ اسلام اور پاکستان کے سلسلہ میں مخلص تھے۔ ان کے سانحہ ارتحال سے ہم بہت مخلص خادم علم، خادم اسلام اور خادم پاکستان سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما وے اور ان سے جو فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا تھا، وہ پہنچتا رہے اور اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی تھیں ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔
مولانا عبد القیوم حقانی
(ماہنامہ القاسم، نوشہرہ)
( ۷ )
ممتاز محقق اور عالم دین، اسٹیٹ بینک کے شعبے کے چیئر مین، سابق ڈائریکٹر دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کے سابق سربراہ اور فیصل مسجد اسلام آباد کے سابق خطیب ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علمی حلقوں میں ان کی جدائی کی خبر سے انتہائی صدمے کی کیفیت طاری ہے۔ آپ کاندھلہ کے علمی خانوادے کا تسلسل تھے۔ آپ کی غیر معمولی قابلیت ، تحقیق اور وسعت خیالی نے آپ کو ہر طبقے میں ہر دلعزیز بنا رکھا تھا۔ جس انداز میں مدارس کے ساتھ آپ کامسلسل رابطہ اور محبت بھر اتعلق تھا ، بالکل اسی طرح ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں اور حکومتی اداروں میں بھی آپ کی بے انتہا پذیرائی تھی۔ سابق صدر ضیاء الحق نے آپ کی قابلیت کی بنا پر آپ کواپنا ترجمان بنایا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بنانے کے ساتھ اہم ذمہ داریاں تفویض کر رکھی تھیں۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں انہیں وفاقی شرعی عدالت کاجج اپائنٹ کیا۔ سابق صدر پرویز مشرف نے انہیں وفاقی مذہبی امور کا وزیر بنایا جس سے ان کی موافقت نہ ہو سکی اور جلد ہی انہیں اس سے الگ ہونا پڑا۔
آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے سب سے کامیاب اور ہر دلعزیز سربراہ رہے۔ آپ کے زمانے میں یونیورسٹی کے ماحول میں اسلامی ثقافت کا رنگ غالب رہا۔ آپ نے گو پردے کو قانونی حیثیت تو نہ دی، لیکن اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں میں اسلامی لباس کا رجحان ترقی کرتا رہا۔ دعوۃ اکیڈمی بھی آپ کی ڈائریکٹر شپ میں ہی منظم اور فعال ادارے کے طور پر سامنے آئی تھی۔ آج دعوۃ اکیڈمی کے مفید پروگرامز اور ہمہ جہت کارکردگی میں ڈاکٹر صاحب کی خصوصی توجہ کا بڑا دخل ہے۔ ہر محقق علمی شخصیت کی طرح آپ کے نقاد بھی موجود رہے۔ خاص طور پر پرویز دور میں عہدہ قبول کرنے پر ان پر بہت تنقید ہوئی۔ خاص طور پر ممتاز محقق محمد موسیٰ بھٹو نے اس حوالے سے خصوصی مکاتبت فرمائی تھی جو ان کی کتاب میں شائع ہو چکی ہے۔ ان خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اپنے اسلاف کی طرح تحمل اور تواضع کے پیکر تھے۔ کسی موقع پر وہ تنقید کی وجہ سے اشتعال کا شکار نہ ہوئے۔ حفظِ مراتب کے ساتھ باسلیقہ گفتگو کا اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ موصوف کو اردو کے علاوہ عربی اور انگریزی تحریر وتکلم پر یکساں عبور تھا۔
عالمی کانفرنسوں اور سیمینارز میں کسی بھی زبان میں بے تکلف گفتگو ان کا طرۂ امتیاز تھی ۔ موصوف نے جدت پسندی کے نام پر اجماع سے ہٹے ہوئے نظریات کا ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ سیرت، فقہ اور خصوصیت سے فقہ المعاملات میں خصوصی درک رکھتے تھے۔ ان کے محاضرات( لیکچرز) سیرت، فقہ اور معیشت چھپ کر داد تحسین وصول کر چکے ہیں۔ ملک کی کوئی اہم لائبریری نہ ہو گی جس میں ان کی کتب کو خصوصیت سے جگہ نہ دی جاتی ہو۔ کراچی کے معروف علمی ادارہ جامعۃ الرشید کے زیرنگرانی قضا کورس میں انہوں نے جو ساڑھے چار گھنٹے پرمغز بیان کیا تھا، اسے لازوال شہرت ملی تھی۔ یہ بیان پاکستان بھر کے نامور دارالافتاؤں کے جید مفتیا ن کرام کے سامنے کیا گیا تھا جسے اس کی روانی، ٹھوس استدلال اور جامعیت کی وجہ سے بے حد پسند کیا گیا تھا۔ جامعۃ الرشید کے سالانہ کنونشن میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر تقریباً آٹھ ہزار سامعین کے سامنے انہیں دو لاکھ کتابوں پر مشتمل ڈیجیٹل لائبریری اور لیپ ٹاپ دیا گیا تھا۔ ان کی علمی قابلیت کی وجہ سے انہیں مختلف نصابوں کی تشکیل میں شریک کیا جاتا رہا ہے۔
گزشتہ کچھ زمانے سے وہ قطر میں خدمات انجام دے رہے تھے اور گاہے گاہے اسلام آباد، کراچی اور لاہور بھی چکر لگاتے تھے۔ اس بار اسلام آباد میں قیام کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا اور داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے قریب جہالت کا غلبہ ہو گا اور علم اٹھا لیا جائے گا ۔ علم اٹھانے کی صورت یہ ہو گی کہ زمانے کے نبض شناس علما کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت ہم کسی ایسی ہی صورت حال کا شکار ہیں یا انہیں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ ان کی علمی خدمات اور عملی جدوجہد یقیناًاس قابل ہے کہ ہر پاکستانی ان پر رشک کرے، ان سے استفادہ کرے اور امید رکھے کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عملی کام کرنے کا موقع عنایت کیا، وہ ان لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ ان کے درجات بلند فرمائیں اور اپنی عادت کے مطابق قحط الرجال کے اس دور میں ہمیں نئے رجال عطا فرمائیں۔ آمین۔
( ہفت روزہ ’’ضرب مومن ‘‘کراچی)
(۸)
یہ خبر دل ودماغ پر بجلی بن کر گری کہ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی شرعی عدالت کے جج، مایہ ناز استاد، محقق اور دانش ور مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی ۲۶؍ ستمبر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جن چند گنے چنے لوگوں کو سنجیدہ غور وفکر اور اعلیٰ درجے کا افہام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ڈاکٹر محمود احمد غازی اسی عمدہ جماعت کے فرد فرید تھے۔ پاکستان میں ان کے نام اور کام کو جاننے والے دسیوں، ہزاروں لوگ ہیں تو بیرون ملک بھی ان کے قدر دانوں کی کمی نہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی اپنے علم وفضل کی گہرائی اور مزاج کی شرافت اورمتانت کے حوالے سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ اب جبکہ سنجیدہ غور وفکر کرنے والے لوگ علمی حلقوں میں دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، ڈاکٹر محمود غازی کے جانے سے یہ کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔
ڈاکٹر صاحب مرحوم ۲۰۰۲ء تا ۲۰۰۴ء وفاقی وزیر مذہبی امور رہے۔ انھوں نے حکومت میں رہتے ہوئے پرویز مشرف کے، دینی مدارس کے نصاب ونظام تعلیم کے خلاف ناپاک منصوبوں کو جس حکمت سے ناکام بنایا، وہ ان کے اخلاص کا غماز ہے۔ وزارت سے سبک دوشی ان کے اسی ’’جرم‘‘ کی سزا تھی۔ ۲۰۱۰ء میں انھیں وفاقی شرعی عدالت کا جج مقرر کیا گیا۔ انھوں نے چالیس سے زائد ممالک کے سفر کیے، اندرون وبیرون ملک مختلف موضوعات پر ہونے والی ایک سو سے زائد کانفرنسوں میں شرکت کی۔ اسلامی قوانین، اسلامی تعلیم، اسلامی معیشت اور اسلامی تاریخ سے متعلق اردو، انگریزی، عربی میں تیس سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ قادیانیت کے رد میں ایک مستقل کتاب انگریزی میں تحریر کی۔ وہ اپنی شاندار زندگی کا سفر ساٹھ سال میں مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
غم کی اس گھڑی میں مجلس احرار اسلام پاکستان کے امیر حضرت پیر جی سید عطاء المہیمن بخاری، سیکرٹری جنرل عبد اللطیف خالد چیمہ، مدیر نقیب ختم نبوت سید محمد کفیل بخاری اور راقم، مرحوم ڈاکٹر صاحب کے اہل خانہ اور ان کے بھائی ڈاکٹر محمد الغزالی سے تعزیت مسنونہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ دین اسلام کے حوالے سے ان کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین
محمد عابد مسعود ڈوگر
(ماہنامہ نقیب ختم نبوت، ملتان)
ایک نابغہ روزگار کی یاد میں
پروفیسر ڈاکٹر دوست محمد خان
مجھے یاد نہیں کہ محمود غازی کو میں نے پہلی بار کہاں دیکھا، کہاں سنا، لیکن اتنا یاد ہے کہ علوم الاسلامیہ کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میں نے بر صغیر پاک وہھند کی جن علمی شخصیات کی تصنیفات و تالیفات سے سب سے زیادہ استفادہ کیا، ان میں محمود غازی صاحب کا اسم گرامی سر فہرست ہے۔ ان کے جاری کردہ سر چشمہ علم سے فیض یاب ہونے کی بنا پر میری شدید خواہش تھی کہ اپنے ان دیکھے روحانی استاد کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع جلد سے جلد حاصل کرلوں۔ آخر وہ دن آہی گیا۔ میں اس وقت شیخ زاید اسلامک سنٹر پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر تھا اور میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سعید اللہ قاضی نے مجھے نصیحت کے طور پر فرمایا تھا کہ علما اور اسکالرز کے لیکچرز اور سیمینارز وغیرہ سے جب اور جہاں موقع ملے، خوب خوب استفادہ کیا کرو کہ سیمینارز کے محاضرات میں علما و فضلا کئی کتب کا نچوڑ بہت مختصر وقت میں پیش کرتے ہیں۔ اس جذبے اور تڑپ کو دل میں سمائے ہوئے میری کوشش ہوتی تھی کہ پشاور شہر میں کہیں بھی کسی عالم فاضل شخصیت کا ورود سعید ہو تو میں پہنچ جاؤں۔
ایک دن میرے ایک عزیز دوست نے مجھے وہ خوشخبری سنائی جس کے لیے میں ایک مدت سے انتظار میں تھا۔ محمود غازی کو جامعہ پشاور کی تنظیم اساتذہ کے منتظمین نے لیکچر کے لیے مدعو کیا تھا۔ میں مقررہ جگہ پر پہلی فرصت میں پہنچ کر یہ سوچتا رہا کہ وفور شوق ملاقات کا تقاضا ہے کہ محمود غازی کی آمد پر میرا دل زور سے دھڑکے اور وہی ہوا۔ جونہی اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا کہ ہمارے مہمان گرامی پہنچ چکے ہیں، میں نے ہال کے گیٹ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ میانے قدو قامت کی ایک شخصیت سفید اجلے کپڑوں اور سیا ہ شیروانی میں ملبوس سر پر ملائی (ملائشیا) طرز کی سیاہ ٹوپی پہنے تین چار پروفیسروں کے جھرمٹ میں ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ غازی صاحب جب اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے تو بلا مبالغہ میں کافی دیر تک آپ کے سراپے کا جائزہ لے لے کر آپ کی پڑھی ہوئی تحریروں میں آپ کو دیکھتا، تولتا اور جانچتا رہا۔ میں یہاں اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ عام طور پر یہ کہاجاتا ہے کہ جن کی تحریروں سے کوئی متاثر ہوجائے، ان سے ملاقات کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ یہ خوف دل میں رکھتے ہوئے لیکچر کے بعد غازی صاحب سے مصافحہ کے لیے احباب آگے بڑھے تو میری باری بھی آگئی۔ میں نے معانقہ کے لیے ہاتھ پھیلائے تو آپ نے اسی گرم جوشی کے ساتھ بزرگانہ شفقت فرمائی۔اس واقعہ کو کئی عشرے گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی ان کی یادیں میرے قلب وذہن کا احاطہ کرتی ہیں تو آپ کا وہی اجلا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور لاشعور سے ایک آواز سی اٹھتی محسوس ہوتی ہے کہ ’’رفتید ولے نہ از دل ما‘‘۔
فیض کے اس آفاقی شعر کا پہلا مصرعہ : ’’اے ہم نفسانِ محفل ما‘‘ اس لیے نہ لکھ سکا کہ ہم اتنے خوش قسمت کہاں ٹھہرے کہ محمود غازی کی محفل کے ہم نفس ہونے کا دعویٰ کریں۔ بہرحال اس پہلی ملاقات کے بعد محمود غازی صاحب جب بھی پشاور آتے، ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا، لیکن چونکہ آپ ایک مصروف ترین عالمی علمی شخصیت تھے، لہٰذا ملاقات عموماً برسوں بعد ہوتی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ کم ملاقاتوں کے باوجود ان کے ذہن کی لوح پر ایک کونے میں مجھ جیسے غریب العلم کا نام بھی کندہ ہو گیا تھا اور یہ یقیناًان کی عظمت تھی۔
میں عمداَ محمود غازی کے علمی کارناموں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان بھر کی علمی شخصیات نے اس کام کو بطریقہ احسن پایہ تکمیل تک پہنچایا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی حیات مستعار و مختصر میں کچھ کام ایسے انداز میں کیے کہ شاید ہی کوئی دوسرا آپ کے بعد کر سکے۔ عالم اسلام میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے بعد اپنے لیکچرز وخطبات کے ذریعے جس شخصیت نے عالم اسلام کے طالبان علم کو اپنی طرف کھینچا، وہ محمود غازی ہی تھے۔ آپ نے ’’محاضرات‘‘ کے نام سے سیرت، معاشیات، فقہ اور حدیث پر جو علمی ذخیرہ امت مسلمہ کے لیے چھوڑا ہے، وہ یقیناًخیر کثیر اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا دوسرا کارنامہ یہ کہ آپ صدر پرویز مشرف جیسی Persona non grata کی کابینہ کے ان ایام میں حصہ بنے جب یہ کام ’’آبیل مجھے مار‘‘ کے مصداق تھا۔ سنجیدہ علمی حلقوں میں آپ کے اس فیصلے پر تنقید بھی ہوئی اور اسے حب جا ہ و اقتدار سے بھی تعبیر کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں عالمی طاقتوں کی طرف سے جتنا دباؤ منبر و محراب اور مدارس و اسلامی شعائر پر تھا، اس کا حکمت کے ساتھ مقابلہ کرنے، تدبیر و تدبر کے ساتھ اسے ناکام کرنے اور مدارس کی حفاظت کے لیے محمود غازی نے جو کردار ادا کیا، اس کا اندازہ مستقبل کا غیر جانب دار مورخ صحیح طور پر کر سکے گا۔ اس کا ثبو ت یہ بھی ہے کہ جونہی وہ سخت مرحلہ گزر گیا، آپ نے خود ہی استعفا پیش کر دیا۔ پاکستان کے بعض جید علماء کو اس کا احساس بھی تھا اور اندازہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب غازی صاحب نے وزارت سے استعفا دیا تو محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے آپ کو اپنے مشن کی بخوبی تکمیل پر مبارک باد پیش کی جس کے جواب میں محمود غازی نے فرمایا کہ لوگ تو مجھ پر تنقید کررہے ہیں اور آپ مبارک باد دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، جو آپ کے مشن سے واقف ہیں، وہی مبارک باد دے سکتے ہیں۔
تیسر ا بڑا کام یہ کہ آپ کا دل امت کی معاشی زبوں حالی پر تڑپتا تھا۔ آپ نے امت مسلمہ کو بالعموم اور مملکت خداداد کو بالخصوص سودی معیشت سے نجات دلانے کے لیے محاضرات معیشت پیش کرنے کے علاوہ اسلامی بینکاری کے فروغ سے متعلق اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں اس کے لیے قانون سازی سے لے کر عملی نفاذ تک دن رات محنت کی، لیکن اس کے باوجود جب ۱۹۸۵ء کے الیکشن کے بعد اس اہم کام کی طرف دین دار طبقے نے بھی توجہ نہیں کی تو محمود غازی صاحب اس کا ذکر ادب کا دامن ہاتھ میں تھامے، لیکن بہت ترش روئی کے ساتھ اور تیکھے انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر جناب صبغت اللہ صاحب کے دستخط سے ۱۰ جون ۱۹۸۴ء کو ایک سر کیولر جاری ہوا جس کے مطابق یکم جولائی ۱۹۸۴ء سے تمام بینک اپنے کاروبار کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کرنا شروع کردیں گے اور یکم جولائی ۱۹۸۵ء سے مکمل طور پر اسلامی بینکاری شروع ہو جائے گی۔ پھر کسی کو غیر اسلامی بینکاری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس نئے نظام پر مکمل عمل درآمد کا آغاز ہونے سے پہلے مارچ ۱۹۸۵ء میں انتخابات ہوگئے اور جمہوریت کی نیلم پری آگئی اور لوگ اس سے بغل گیر ہو گئے۔ ہمارے علماء کرام اور اسلامی اور دینی جماعتوں کے ارکان بھی جمہوریت کی اس نیلم پری کے استقبال میں مگن ہوگئے۔ سب اہل دین، اہل جبہ و دستار اور احیاے اسلام کے علم بردار بھی، تجدید کے علم بردار بھی سب اس اصلی کام کو بھول گئے اور جمہوریت کے احیا میں تن من دھن سے مصروف ہوگئے۔ غالب نے کہا ہے نا آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے ۔ جب میں اس داستان کو بیان کرتاہوں تو میرے دل میں بھی درد سوا ہوجاتا ہے، اس لیے میری زبان میں تھوڑی سی تلخی آجاتی ہے۔‘‘
عالم اسلام کے امیر ممالک کی دولت کے انبار کو نالیوں میں بہتے اور امریکی تجوریوں میں منتقل ہوتے دیکھ کر اور اوپر سے ۱۹۸۲ء میں بنائے جانے والے ایک امریکی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے جس کے مطابق اگر کسی غیر ملکی کی امریکی بینکوں میں دس ملین ڈالر سے زیادہ رقم جمع ہو تو وہ اس سے سال میں دو فیصد سے زیادہ نہیں نکال سکتا، غازی صاحب پر کیا گزرتی ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجیے:
’’اس امریکی قانون کو پڑھ کر مجھے فوراً ایک دھچکا سا لگا کہ یہ تو میرے مسلمان بھائیوں کی دولت کھا جانے کا اور لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ میں نے اس قانون کا متن بہت تگ و دو کر کے حاصل کیا۔ اس کا عربی ترجمہ کیا، ایک مذکرہ تیار کیا اور ایک یادداشت اس موضوع پر لکھی۔ اس میں ان حضرات سے گزارش کی (ان حضرات سے جن کے ملکوں کی دولت وہاں جمع ہے) کہ آپ کی جتنی بھی دولت اس وقت وہاں جمع ہے، اس سے دو فیصد سے زیادہ تو آپ کبھی بھی نکال نہیں سکتے۔ اگر نکالیں گے تو آپ کی ساری دولت قانون کے مطابق منجمد ہوکر ضائع ہو جائے گی۔ کم از کم آپ اتنا تو کرسکتے ہیں کہ آئندہ آپ اپنی دولت وہاں جمع نہ کروائیں اور جو جمع ہے، اس کو کم از کم ڈیڑھ پونے دو فیصد سالانہ کے حساب سے نکالتے رہیں۔ اس طرح ساٹھ پینسٹھ سال کے عرصے میں امید ہے کہ آپ اپنی دولت واپس لے سکیں گے۔ یہ سب کچھ میں نے بڑی محنت سے لکھا۔ اس زمانے میں نہ کمپیوٹر ہوتے تھے، نہ فوٹو سٹیٹ مشینیں آسانی سے دستیاب ہوتی تھیں۔ بہت بھاگ دوڑ کرکے، بڑی محنت سے اس یاد داشت کو بہت خوبصور ت ٹائپ کرایا اور پھر سات آٹھ ملکوں کے سفارت خانوں کو ان کے ذریعے وہاں کے حکمرانوں کو بھیجا، لیکن کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا۔ کہیں سے یہ رسید بھی نہیں آئی کہ تمھارا خط مل گیا ہے۔ کسی کے سیکرٹری یا چپڑاسی کی طرف سے بھی یہ اشارہ تک نہیں ملا کہ آپ کا خط مل گیا ہے، شکریہ! ‘‘
اس مثال سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بھائیوں کی کتنی دولت وہاں جمع ہے اور مغربی بینکوں کا نظام کیسے چل رہا ہے اور اس بارے میں ان ممالک کے حکمرانوں کے سوچنے کا انداز کیا ہے اور امت مسلمہ کے مستقبل سے ان کی کس قدر ذہنی و فکری وابستگی ہے۔ میرے ساتھ ان کی آخری ملاقات پشار کے موضع حسن گڑھی میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار کے جنازے پر ہوئی۔ ظہر کے نماز میں مجھے ان کے ساتھ قیام و قعدے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس ملاقات میں میرے ساتھ سال ڈیڑھ سے کیے ہوئے وعدے کی تجدید بھی ہوئی۔ میری شدید خواہش تھی کہ شیخ زاید اسلامک سنٹر پشاور یونیورسٹی کے آڈیٹورم میں ’’جہاد و دہشت گردی میں فرق عصر حاضر کے تناظر میں‘‘ کے عنوان پر آپ سے ’’خطبات خیبر‘‘ دلوا کر امت کی راہنمائی کا وسیلہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خطبات الہ باد، خطبات مدراس اور خطبات بہاول پور کی فہرست میں شامل ہوا جائے۔ یہ اہم کام مارچ ۲۰۱۱ء میں شروع ہونا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہ تھا۔ اب یہ استدعامولانا زاہد الراشدی صاحب سے کرچکا ہوں۔ اللہ کرے کہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچے۔ آخری بات یہ کہ عقیدۂ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ کی مساعی اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے اس اہم ترین کام کے آثار جنوبی افریقہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ کی مغفرت کے لیے قبول فرمائے ۔ آمین ثم آمین۔
برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی
مارچ ۲۰۱۱ء
توہین رسالت پر سزا کا قانون
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
توہین رسالت کی سزا کے قانون کے خلاف ملک میں مختلف حلقے سرگرم عمل ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو سرے سے توہین رسالت کو جرم ہی نہیں سمجھتے اور اس پر کسی سزا کو آزادئ رائے، آزادئ ضمیر اور آزادئ مذہب کے منافی تصور کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کے مغربی معیار کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں، بلکہ اس پر ظالمانہ قانون اور کالا قانون ہونے کی پھبتی بھی کستے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرز فکر کے نمائندہ دانش ور سیکولر جمہوریت کو عدل وانصاف کا واحد معیار تصور کرتے ہوئے سوسائٹی کے اجتماعی معاملات اور ریاست وحکومت کی پالیسیوں میں مذہب کا کوئی حوالہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حکومتی وریاستی امور میں دینی تعلیمات کا ہر حوالہ ختم کر دینے کی مہم چلائے ہوئے ہیں۔
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے تناظر میں اس نقطہ نظر کے علم برداروں سے یہ گزارش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک سیکولر نقطہ نظر کی ترجمانی کا تعلق ہے تو سیکولر ذہن اور سیکولر جمہوریت کا پرچار کرنے والے دانش ور اور سیاسی راہ نما اس ملک میں ہمیشہ رہے ہیں اور آبادی میں ان کا تناسب کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، انھیں اپنی بات کہنے اور اپنے موقف کے لیے مہم چلانے کا حق بھی ہمیشہ حاصل رہا ہے۔ قومی سیاسی منظر اور قومی پریس اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں سیکولر جمہوریت کا پرچار اور سوسائٹی کے اجتماعی معاملات میں مذہب کے کردار کی نفی کرنے والے ہر دور میں اپنے موقف کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سوسائٹی نے ان کی اس بات کو کبھی قبول نہیں کیا اور جب بھی سیکولر جمہوریت اور قومی ومعاشرتی معاملات میں اسلام کے کردار کی ضرورت پر بات ہوئی ہے، قوم کی غالب اکثریت نے فیصلہ اسلام کے معاشرتی کردار کی حمایت میں ہی کیا ہے، لیکن ذوق وسلیقہ اور احترام وآداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیکولر جمہوریت کی بات کرنے والوں کا راستہ کبھی نہیں روکا گیا اور انھیں ہر فورم پر اپنی بات کہنے کا حق دیا گیا ہے۔ تاہم توہین رسالت کو آزادئ رائے اور آزادئ اظہار کے دائرے کی چیز شمار کرنا اور اس پر سزا کے قانون کو ’’کالا قانون‘‘ کہنا ایک بالکل مختلف معاملہ ہے اور یہ پہلو سب لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ تعلق صرف رسمی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی تمام تر عملی کمزوریوں کے باوجود اسلام کے معاشرتی کردار پر ایمان رکھتے ہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ان کی ذاتی عقیدت ومحبت ہر دور میں شک وشبہ سے بالاتر رہی ہے، اس لیے سیکولر حلقے اپنے موقف کا اظہار ضرور کریں، مگر مسلمانوں کے جذبات کو بار بار آزمانے سے بہرحال گریز کریں کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔
دوسرا حلقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں نفس قانون پر کوئی اعتراض نہیں اور ہم بھی توہین رسالت کو حرام سمجھتے ہوئے اس پر موت کی سزا کی حمایت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس قانون کا استعمال ان کے بقول زیادہ تر غلط ہو رہا ہے اور اس کا استعمال ذاتی انتقام، خاندانی دشمنیوں اور علاقائی وطبقاتی مخاصمتوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ طبقہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طبقے کا کہنا ہے کہ سرے سے اس قانون کا ہی خاتمہ ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے طبقے کا موقف یہ ہے کہ قانون باقی رہے، لیکن اس کے ممکنہ غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس قانون کے نفاذ کے طریق کار کو بدل دیا جائے۔
اس تناظر میں گزشتہ جنوری کے دوران میں مولانا قاری محمد حنیف جالندھری نے جامعۃ الخیر لاہور میں مسیحی علما اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کرام کے درمیان اس مسئلے پر مکالمہ کا اہتمام کیا جس میں بشپ الیگزینڈر جان ملک اور بشپ منور سمیت نصف درجن کے لگ بھگ مسیحی راہ نماؤں نے شرکت کی جبکہ دوسری طرف سے مولانا مفتی محمد خان قادری، مولانا عبد المالک خان، رانا شفیق پسروری، مولانا یاسین ظفر، مولانا رشید احمد لدھیانوی، مولانا قاری روح اللہ، جناب لیاقت بلوچ، مولانا محمد امجد خان، علامہ حسین اکبر نجفی، مولانا قاری محمد حنیف جالندھری اور راقم الحروف سمیت دیگر علما شریک ہوئے۔ اس موقع پر اس مسئلے پر تفصیلی بحث ہوئی جس میں دونوں فریق اس بات پر پوری طرح متفق تھے کہ توہین رسالت جرم ہے اور اس کی سنگین سزا پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، البتہ دونوں فریقوں کے اپنے اپنے تحفظات تھے جن کا ذکر کیا گیا اور باہمی وعدہ ہوا کہ دونوں فریق ان پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اگلی کسی ملاقات میں ان تحفظات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔
مسیحی راہ نماؤں نے اس تحفظ کا اظہار کیا کہ ان کے بقول اس قانون کا سب سے زیادہ استعمال مسیحی کمیونٹی کے خلاف ہو رہا ہے اور ان کے خیال میں اسے مسیحی لوگوں کو مختلف حوالوں سے انتقام اور تذلیل کا نشانہ بنانے کے لیے بطو ر خاص استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جب کسی واقعہ پر عوامی اشتعال کے اظہار کے موقع پر مسیحی آبادی اور بستیاں عمومی سطح پر قتل وغارت اور آتش زنی کا نشانہ بنتی ہیں تو مسلمان علما مظلوموں کو بچانے کی بجائے خاموش تماشائی بن جاتے ہیں، بلکہ کچھ علماء کرام اس عوامی اشتعال کو بڑھانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ایک مسیحی راہ نما نے اس موقع پر کہا کہ ہم توہین رسالت پر موت کی سزا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جب ہم عوامی اشتعال کی زد میں ہوتے ہیں اور اس وقت ہماری دادرسی نہیں ہوتی اور کوئی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارۂ کار باقی نہیں رہتا کہ ہم سرے سے اس قانون کو ہی ختم کرنے کا مطالبہ کریں جو اس صورت حال کا ذریعہ بن رہا ہے۔
ہماری طرف سے اس تحفظ کا اظہار کیا گیا کہ وہ سیکولر لابی جو پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے درپے ہے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون سمیت ہر اس قانون کو ختم کرانے کے لیے کوشاں ہے جس میں دینی تعلیمات کا کوئی حوالہ موجود ہے، مسیحی مذہبی راہ نماؤں کی طرف سے تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کا مسلسل مطالبہ اس سیکولر لابی کی تقویت کاباعث بن رہا ہے جبکہ یہ بات خود مسیحی تعلیمات اور بائبل کی تصریحات کے بھی منافی ہے۔
جہاں تک اس قانون کے غلط استعمال کا تعلق ہے تو ملک میں دیگر بہت سے قوانین کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس بات کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ ہمارے کلچر سے ہے جس کی جڑیں نوآبادیاتی دور میں پیوستہ ہیں کہ اس کلچر کو کرپشن اور بددیانتی کا خوگر بنا دیا گیا ہے۔ اس کا علاج ہمارے قومی راہ نماؤں نے مذہبی اقدار کی بحالی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں تلاش کیا، مگر گزشتہ ساٹھ برس سے معاشرتی معاملات میں مذہب کو کردار ادا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ یہ کہنا کہ قانون کا استعمال مذہب کے حوالے سے اور مذہبی راہ نماؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے، خلاف حقیقت بات ہے کیونکہ ۳۰۲ اور ۳۰۷ کی دفعات بھی ذاتی انتقام، خاندانی دشمنیوں اور گروہی رقابتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں کون سا مذہب کردار ادا کرتا ہے اور مذہبی راہ نماؤں کا کون سا طبقہ اس کی ترغیب دیتا ہے؟ یہ ایک معاشرتی رویہ ہے جس کا مذہب یا مذہبی حلقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اگر ۲۹۵۔سی کا بھی کسی جگہ غلط استعمال ہو جاتا ہے تو اسے مذہب یا مذہبی راہ نماؤں کے کھاتے میں ڈال دینا کہاں کا انصاف ہے؟
پھر اس قانون کا استعمال صرف اقلیتوں کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کہلانے والوں کے خلاف بھی ہوتا ہے اور اگر اس قانون کے غلط استعمال کی صورت فی الواقع ہے تو یہ ہے کہ بعض مسلمان محض فرقہ وارانہ اختلافات اور تعصب کے باعث اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف اس قسم کے مقدمات درج کرا دیتے ہیں، جیساکہ حال ہی میں ایک مقدمہ میں ایک فرقہ کے مولوی صاحب کو اس جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے کہ انھوں نے مسجد کی دیوار سے دوسرے فرقے کے ایک پروگرام کا پوسٹر پھاڑ دیا تھا۔ اکا دکا واقعات میں اس قسم کی صورت حال سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی بنیاد پریہ کہنا کہ توہین رسالت کے قانون کا بالکل ہی غلط استعمال ہو رہا ہے یا صرف اقلیتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ قطعی طو رپر غیر واقعی اور غیر منطقی بات ہے۔
بہرحال اس قانون کے غلط استعمال کا الزام درست ہو یا غلط، دونوں صورتوں میں ہم نے اس پر باہمی گفتگو اور مکالمے کی ضرورت سے کبھی انکار نہیں کیا اور مبینہ طور پر غلط استعمال کی روک تھام کے لیے طریق کار میں کسی ایسی تبدیلی کو مسترد نہیں کیا جس سے نفس قانون متاثر نہ ہوتا ہو، لیکن سرے سے اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ ہمارے نزدیک ان لادین سیکولر حلقوں کے موقف کی حمایت کے مترادف ہے جو سرے سے مذہب کے معاشرتی کردار کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ریاست وحکومت کے تمام معاملات سے مذہب کا حوالہ ختم کر دینے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔
یہاں بشپ آف پاکستان ڈاکٹر اعجاز عنایت کے ایک تفصیلی انٹرویو کے چند اقتباسات نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جسے کراچی کے روزنامہ ’’امت‘‘ نے ۱۱ جنوری ۲۰۱۱ء کو شائع کیا ہے۔ بشپ چرچ آف پاکستان ڈاکٹر اعجاز عنایت نے کہا ہے کہ:
- موجودہ صورت حال کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے جس نے معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر حکومت معاملے کو ابتدا میں ہی سمجھ داری سے حل کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ سلمان تاثیر سمیت دیگر حکومتی عہدیداروں نے طاقت کے زعم میں ایسی باتیں کیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ درحقیقت انھوں نے لاپروائی کا مظاہرہ کر کے اقلیتوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سلمان تاثیر نے آسیہ کے معاملے میں جو مداخلت کی ہے، ہم اس کے طریق کار کو مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر قانون میں کوئی سقم تھا تو انھیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔
- سلمان تاثیر کی جہاں تک بات ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ان کے بیان کی وجہ سے ملک میں لبرل اور انتہا پسند طبقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے جو غیر ضروری اور غیر اہم ہے۔
- میں توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے اکثریت کی حمایت حاصل ہے اور اسے موجود رہنا چاہیے، تاہم جو شخص الزام عائد کرتا ہے، اس کا سب سے پہلے پولوگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ۔ اس کے علاوہ الزام عائد کرنے والے کے الزام کاجائزہ لینے کے لیے علماے کرام کی ایک ہائی پروفائل کمیٹی ہونی چاہیے جو یہ دیکھے کہ الزام کسی دشمنی یا رنجش کی بنا پر تو عائد نہیں کیا جا رہا؟
- مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ روز اول سے ہی ۲۹۵۔ سی کے غلط استعمال کو روکنے کی کوشش کرتے تاکہ آسیہ مسیح اور سلمان تاثیر کے اس مقام تک پہنچنے کی نوبت نہ آتی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اہل اسلام کو معلوم ہوگا کہ ۲۹۵۔ سی کے نفاذ میں اقلیتوں کے تمام ووٹ اس قانون کے حق میں تھے۔ اس وقت بھی ہمیں اس قانون سے کوئی خطرہ نہیں تھا اور آج بھی ہم اس قانون کی عزت کرتے ہیں۔
- عام تاثر یہی ہے کہ سلمان تاثیر بیرونی دنیا کے دباؤ اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایات پر عمل درآمد کر رہے تھے، تاہم میں اس سوچ کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ صدر پاکستان اور حکمرانوں کو میرٹ کی بنیاد پر ملک کے عوام کو انصاف فراہم کرنا چاہیے تاکہ عدل وانصاف کے پیچیدہ نظام کی وجہ سے بے گناہ افراد کو سزا نہ مل سکے۔ میں اپیل کروں گاکہ ہم سب مل کر پاکستان میں عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔
بشپ چرچ آف پاکستان جناب ڈاکٹر اعجاز عنایت کے یہ متوازن اور حقیقت پسندانہ خیالات اس حوالے سے حوصلہ افزا ہیں کہ انھوں نے معروضی صورت حال کا بہتر تجزیہ کیا ہے اور اس سازش کو بروقت بھانپ لیا ہے جو پاکستان میں مسلم اکثریت اور مسیحی اقلیت کے درمیان غلط فہمیوں کو فروغ دینے اور اس کے ذریعے لادینیت کے سیکولر ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مفاد پرست عناصر کی طرف سے مسلسل جاری ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر
ذو الفقار علی بھٹو مرحوم سے تمام تر اختلافات کے باوجود ان کا یہ کریڈٹ ہمیشہ غیر متنازعہ رہا ہے کہ انھوں نے ۱۹۷۳ء کے دستور میں پاکستان کی اسلامی نظریاتی شناخت کو قائم رکھا، قوم سے نفاذ اسلام کا دستوری عہد کیا، عقیدۂ ختم نبوت کے تحفظ کا دیرینہ مسئلہ حل کیا، اسلامی سربراہ کانفرنس کا اہتمام کر کے عالم اسلام کو وحدت اور یک جہتی کا پیغام دیا اور ایٹمی توانائی کے مسئلے پر عالمی دباؤ کی پروا نہ کرتے ہوئے قومی خود مختاری اور ملی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں کے بیانات اور اس کے خلاف ان کی مہم دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کہ شاید پی پی پی اپنے مرحوم بانی اور قائد جناب ذو الفقار علی بھٹو کے کردار سے منحرف ہونے جا رہی ہے ، لیکن ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پر شاہ محمود قریشی اور تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے بارے میں وزیر قانون بابر اعوان کے دوٹوک موقف نے ہمارے خوف اور خدشے کو دور کر دیا ہے اور دل کو تسلی ہونے لگی ہے کہ پی پی پی میں ابھی ایسے راہنما موجود ہیں جو ملی جذبات کو محسوس کرتے ہیں اور نہ صرف ان سے ہم آہنگ ہیں بلکہ ان کی ترجمانی کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔
تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے بارے میں مختلف ریفرنسز اور محترمہ شیری رحمان کی طرف سے قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں جمع کرائے جانے والے بل کے حوالے سے وزارت قانون نے اپنا موقف واضح کرنے کا تقاضا کیا گیا تھا جس پر وزارت قانون کی طرف سے جوابی طور پر پیش کیے جانے والے ریفرنس میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کا مختلف حوالوں سے جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ا ور حضرات صحابہ کرام کا فیصلہ یہی رہا ہے کہ گستاخ رسالت کی سزا موت ہے اور مختلف مواقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ سزا دی گئی ہے۔ پھر مختلف ممالک کے قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں توہین مذہب اور مذہبی شخصیات کی بے حرمتی کو جرم قرار دیتے ہوئے اس پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، برازیل، کینیڈا، مصر، کویت، ملائشیا، مالٹا، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، نائیجیریا، سعودی عرب، سوڈان، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، یمن اور امریکہ کی بعض ریاستیں شامل ہیں۔ ان تمام ممالک میں مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین جرم ہے اور اس جرم پر مختلف نوعیت کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اس لیے پاکستان میں ناموس رسالت کی توہین کو جرم قرار دینے اور اس پر سزا مقرر کرنے کا قانون عالمی روایات کے خلاف نہیں ہے۔
سمری کا اختتام اس پیرا گراف پر ہوتا ہے کہ ’’ان تمام حقائق کی روشنی میں توہین رسالت کی سزا موت آئین کے آرٹیکل ۲۹۵۔سی، پاکستان پینل کوڈ ۱۸۶۰ اور قرآن وسنت کے عین مطابق ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایسے تمام پیرا گراف جو مختلف ریفرنسز میں بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام قانون کی غلط تشریح پر مبنی ہیں، جبکہ اس قانون پر عمل درآمد کے لیے پاکستان میں موثر عدالتی انصاف بھی موجود ہے جو آئین پاکستان، قرآن وسنت اور انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔‘‘ اس تفصیلی جائزے کے ساتھ وزارت قانون نے وزارت اقلیتی امور کے ریفرنس اورمحترمہ شیری رحمان کے پرائیویٹ بل سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ وزارت قانون نے اس ریفرنس کی صورت میں پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے عقائد وجذبات کا تحفظ وترجمانی کی ہے اور اس کے ساتھ ہی سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے بھی ریمنڈ ڈیوس کیس کے بارے میں زمینی حقائق کے خلاف موقف اختیار کرنے سے انکار کر کے کسی قسم کے ملکی و غیر ملکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے جذبات اور قومی حمیت کی ترجمانی کی ہے۔
’’ہم‘‘ اور ’’وہ‘‘ ۔ لبرل حلقوں کے لیے لمحہ فکریہ!
نادیہ ججا
اس وقت پاکستان میں انگریزی زبان کے تمام اشاعتی اور نشری ذرائع ابلاغ میں جنگ کے نقارے بجنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل نے ایک بار پھر سب کو حالات حاضرہ پر گفتگو میں ’’ہم‘‘ اور ’’وہ‘‘ کی اصطلاحات استعمال کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب گورنر کے قتل کی مذمت نہ کی جائے اور لوگوں کو باہر نکل آنے، ڈٹ کر کھڑے ہو نے اور اس ہوا کا رخ تبدیل کرنے پر نہ اکسایا جائے جو پاکستان کے ’’کمزور ذہن اور برین واش کیے ہوئے‘‘ لوگوں کے لیے چلتی ہے، وگرنہ ’’ہم‘‘ سب تباہ وبرباد ہو جائیں گے۔ ’’ہم‘‘ یقیناًبزعم خود لبرل اور ترقی پسند لوگ ہیں۔ ستم ظریفی اوربدقسمتی یہ ہے کہ یہ ’’ہم‘‘ وہ اقلیت ہے جو پاکستان کی چھ عشروں پر محیط تاریخ کے بیشتر حصے میں خاموش تماشائی بنی رہی ہے۔
لیکن ’’وہ‘‘ کون ہے؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں اور ہوا کا رخ دیکھ کر بدلتا رہتا ہے۔ ’’وہ‘‘ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنھوں نے پاکستان کے سابق صدر اور وزیر اعظم ذو الفقار علی بھٹو کی سزاے موت کے خلاف احتجاج کیا تھا، کسی جماعت کے کارکن ہو سکتے ہیں جو صدر جنرل پرویز مشرف کو اقتدار سے اتارنے کے لیے ۲۰۰۷ء اور ۲۰۰۸ء میں سڑکوں پر نکل آئے تھے جنھیں ’’ہم‘‘ روشن خیال، اعتدال پسند اور لبرل ازم کے علم بردار کہتے ہیں۔ ’’وہ‘‘ وہ ۴۰۰۰۰ ہزار افراد بھی ہو سکتے ہیں جنھوں نے توہین رسالت کے قانون کی ممکنہ منسوخی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا تھا۔ تاہم پاکستان کی غالب اکثریت ہونے کے باوجود ’’وہ‘‘ کبھی بھی پاکستان کا حقیقی چہرہ نہیں بن سکتے۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے کراچی کے ان چالیس ہزار لوگوں کی مثال آتی ہے جو توہین رسالت کے قانون کو منسوخ کیے جانے کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے اور جنھیں ایک مبصر نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ وہ محض مدرسوں کے طلبہ اور سیاسی کارکن ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے جو تبصرے سامنے آئے، ان کا پہلے ہی سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ’’ہم‘‘ پھر خواب غفلت سے جاگے اور اخلاقی طور پر بالاتر اور بزعم خود حق پر ہونے کا ڈھول پیٹنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم مبصرین کے لب ولہجے اور الفاظ کے چناؤ کو مد نظر رکھیں تو لگتا ہے کہ ’’ہماری‘‘ طرف سے ’’انھیں‘‘ ناروادار اور شیطانی مخلوق کہنے میں بس تھوڑی سی کسر ہی رہ گئی تھی۔
دریں اثنا مقامی اور غیر ملکی مبصرین نے ملک میں لبرل اور ترقی پسند طبقے کی حالت زار کا نقشہ کھینچنے کے لیے شاید ہی کوئی استعارہ اور تشبیہ چھوڑی ہو، چاہے اس کا حوالہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور انھیں ’’نابود ہونے کے خطرے سے دوچار نوع‘‘ اور ’’انتہا پسندی کا کینسر‘‘ سے لے کر موہی کن اور انقلاب فرانس کی باقیات جیسے القابات سے نوازا گیا۔ لیکن ہم اتنے احمق کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ سوچیں کہ سلمان تاثیر کے قاتل ملک ممتاز حسین قادری نے جس نارواداری کا مظاہرہ کیا، وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی یا یہ کہ اس کی جڑیں ۱۹۸۰ء کی دہائی میں سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی بزعم خود ’’اسلامائزیشن‘‘ کی پالیسیوں میں نہیں ہیں؟ غازی علم الدین شہید یاد ہے جس سے ممتاز قادری اور اس کے حمایتی متاثر تھے اور جس نے ۱۹۲۹ء میں اپنے دوستوں کے ساتھ سکہ اچھال کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ توہین رسالت پر مبنی مواد شائع کرنے والے ہندو پبلشر کو قتل کرنے کے لیے کون جائے گا؟ ۱۹۵۰ء کی دہائی میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے احمدی فرقے کے خلاف ہونے والے فسادات بھی یاد ہیں، جس فرقے کے جائز ہونے پر اکثریت کو اعتراض ہے اور جب تک وہ اپنے احمدی اور غیر مسلم ہونے کا اعلان نہ کریں، انھیں پاسپورٹ بھی جاری نہیں ہو سکتا؟
مزیددو ہفتوں کے اندر سلمان تاثیر کی موت کی خبر پرانی ہو جائے گی۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ’’ہم‘‘ میں سے کوئی بھی اس مسیحی خاتون آسیہ نورین کی حمایت میں کھڑا نہ ہوتا جسے توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے اور جس کی سلمان تاثیر حمایت کر رہے تھے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی رزمیہ فضا میں کوئی شخص ایسا بھی تھا جو اپنی موت تک اس کی حمایت میں کھڑا رہا۔ جو ستم ظریفی ابھی تک چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کھائی میں دھکا قدامت پرستوں نے نہیں دیا۔ ایسا کرنے والے ’’ہم‘‘ اور ہمارا باقی سارے ملک سے بے پروائی کا رویہ ہے۔ تاریخ نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ بزدلی ہمیشہ ’’ہم‘‘ لبرل لوگوں نے دکھائی ہے اور جب بھی سیاسی مصلحت اور اصولوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا وقت آیا تو ہم نے ہمیشہ سیاست کو چنا۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں ہم خود بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ امکانات انتہائی کم ہیں کہ ’’ہم‘‘ لبرل لوگ نافذ کی گئی، بلکہ نافذ نہ کی گئی پالیسیوں کا بوجھ اٹھا سکیں۔
اس وقت ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں اور مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ’’ہم‘‘ اور ’’وہ‘‘ کی دیواروں کو گرا کر ’’ایک‘‘ بننا ہوگا۔ ’’وہ‘‘ بھی اسی طرح اس قوم کے افراد ہیں جس طرح ’’ہم‘‘ ہیں اور انھیں بھی اپنی رائے کے اظہار کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں حاصل ہے۔ ان کی ہستی کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم اب مزید انکار کی کیفیت میں نہیں رہ سکتے۔ ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ یہ کام اگرچہ آسان نہیں ہے، لیکن جیسا کہ قدیم چینی فلسفی لاؤتسو کا قول ہے، ہزار میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے اور زیر بحث مسئلے میں یہ قدم ’’قبولیت‘‘ ہے۔
(ماخذ: کامن گراؤنڈ نیوز سروس، ۲۱؍ جنوری ۲۰۱۱ء)
ایک تلافی نامے کا معذرت خواہانہ جائزہ
پروفیسر میاں انعام الرحمن
واقعہ کچھ یوں ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان، پنجاب شاخ لاہور کے زیرِ اہتمام ۸ مئی ۲۰۱۰ بروز ہفتہ ’’صوفی ازم کی عوامی بنیادیں‘‘ کے موضوع پر ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے ممتاز دانش وروں نے’’ گراں قدر‘‘ مقالات پڑھ کر صوفیا کو ایصالِ ثواب کیا۔ غالباً ثواب کے ایصال میں کافی کمی رہ گئی تھی جس کی تلافی کی ذمہ داری یونی ورسٹی آف گجرات کے سپرد کی گئی۔ اس وقت ہمارے زیرِ نظر یہی’’تلافی نامہ‘‘ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ تلافی نامے کا سرورق کیا ہے؟ اچھا خاصا طلسم کدہ ہے۔ پھر ہماری کیا مجال کہ اس کے سحر میں ڈوبے بغیر صوفیانہ خوش بیانیوں تک رسائی پا لیں۔ اس لیے لامحالہ ہمیں سلوک کی اس منزل سے گزرنا پڑا جہاں صوفی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ تمام قارئین کو اس ذہنِ رسا کو لازماً ایصالِ ثواب کرنا چاہیے جس نے ہم جیسے پھسڈی کو بھی صوفیانہ واردات کے ’’شاملِ حال‘‘ کرنے سے پہلے پہلے سرورق کے ’’حال‘‘ میں غلطاں کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں خوب غوطے لگوائے ہیں۔ دیدہ زیب کالے نیلگوں سرورق پر دھمال ڈالتے اجلے اجلے چٹے سفید صوفی ہیں، جن کے اوپر جلی حروف میں کندہ ہے:
تدوین و ترتیب: شیخ عبدالرشید
رہنمائی:الطاف احمد قریشی
ہم صوفیا کے مانند حیرت زدگی کے ’’حال‘‘ میں ہیں کہ خیر سے ’’شیخ‘‘ تو عبدالرشید صاحب ہیں لیکن ’’راہنمائی‘‘ کا قرعہ جناب الطاف احمد قریشی کے نام نکلا ہے۔
ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا
بات یہ ہے کہ شیوخ جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں، بازی گروں کی گرد بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے ان کی مرشدی چھپائے نہیں چھپتی اور یہاں بھی نہیں چھپ سکی۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ تلافی نامہ میں جہاں جہاں حضرت شیخ کی مرشدیت کی گرفت کم زور پڑی ہے وہاں وہاں ان کے مریدوں کی’’ عقیدت مندی‘‘ نے خوب دھما چوکڑی مچائی ہے، پروف خوانی کی لن ترانی ہی دیکھ لیجیے۔ بقول شخصے:
حرف کو کاغذی سیاہ کند!
دل کہ تیرہ است کے چو ماہ کند
(جو حروف اچھے بھلے کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، وہ تاریک دل کو کیوں کر روشن چاند کا ہمسر بنا سکیں گے)
صاحبو! صوفیانہ واردات کے ترجمانوں نے تلافی نامہ کے اچھے خاصے مہنگے کاغذکے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو بوٹوں والے دساتیر کے ساتھ کرتے چلے آئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ حرف، لفظ، جملہ، ابلاغ کا وسیلہ بنتاہے۔ لیکن جب یہ وسیلہ، صوفیانہ واردات کا اظہار کرتا ہے تو محض مخل ہوتا ہے۔ اس لیے معزز قارئین ’’شاملِ حال‘‘ ہونے سے پہلے پہلے یقین کر لیجیے کہ آنے والی سطروں میں بہت آسانی سے کاغذ سیاہ کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے کہ ان میں عمیق روحانی تجربات کے انکشاف کی ترجمانی کا ’’حق‘‘ ادا کیا گیا ہے۔
اس تلافی نامہ کے مدون و مرتب شیخ عبدالرشید کی تحریروں کی بابت البتہ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان میں عموماً فکر اور ادبیت کا امتزاج پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ حالاتِ حاضرہ سے واقفیت کا بھی پورا پورا اہتمام موجود ہوتا ہے۔ یہاں بھی شیخ صاحب نے حرفِ اول (جو حرفِ آخر بھی ہو سکتا تھا) کے عنوان سے تعارفی کلمات میں اپنے قلم کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ فرماتے ہیں:
’’بدامنی، فساد اور دہشت گردی کا آغاز چونکہ انسانی دل و دماغ میں ہوتا ہے اس لیے امن کی فصیلیں بھی انسان کے دل و دماغ ہی میں تعمیر ہونی چاہئیں۔ ......بیشتر صوفی اپنی روزی خود کماتے تھے ااور معاشی طور پر دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ ان کی نظر میں دنیا اور دولت مطلقاً بری نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاؒ فرماتے ہیں ترکِ دنیا یہ نہیں کہ انسان ننگا پھرے اور لنگوٹ باندھ لے۔ ترکِ دنیا یہ ہے کہ کھائے پےئے، دوسروں کو کھلائے اور پہنائے اور زخمی دلوں پر شفقت اور مستحقین کی مدد کرے۔ ......صوفیا نے بڑے بڑے جابر حکم رانوں کے سامنے کلمہ حق کہ کر عوام کے حقوق کی ترجمانی کی ہے۔ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ یوں انہوں نے اکثر آمروں اور جابروں کے دور میں ایک طور سے حزبِ اختلاف کا کردار ادا کیا ہے۔‘‘(حرفِ اول:ص۱۲، ۱۶)
تلافی نامہ کے ’’افتتاحیہ‘‘ میں جناب الطاف احمد قریشی نے سوالات کی آڑ میں ’’راہنمائی‘‘ کے فرائض سرانجام دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کا کہنا ہے کہ:
’’سوال یہ ہے کہ سیاسی عروج اور زوال کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ صوفی روایات کسی قوم کے سیاسی عروج یا زوال کا باعث بنی ہوں؟ خود صوفی ازم کی روایت نے کس قسم کے سماج میں جنم لیا اور اس روایت نے برصغیر اور خصوصاً پاکستانی سماج میں کیا کردار ادا کیا؟کیا ہمارے سیاسی زوال کا سبب صوفی روایات کا زوال بنا؟ یا پھر برصغیر کے صوفیوں نے اپنے اپنے وقتوں کی آمریتوں اور شہنشاہیتوں کے خلاف مزاحمت کی؟ یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے اس دور میں عالمی طاقتیں ہم جیسے ملکوں کے وسائل پر تسلط قائم کرنے کے لیے ہمیں عقیدوں کے جھگڑوں میں الجھانے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ہمارے سیاسی زوال کا سبب اقتصادیات کے شعبہ میں ہماری کم فہمی ہے یا صوفی روایات کا معدوم ہونا اس کا باعث ہے؟‘‘(افتتاحیہ:ص۲۲،۲۳)
سوالات بہت اہم ہیں اور ذہنِ رسا کا پتہ دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سوالات اٹھانے، تلاشنے اور کھوجنے کی جستجو، طواف کے مانند اس امر سے متعین ہوتی ہے کہ ان کا مرکز کہاں ہے؟ اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ کولہو کے گرد بیل کا گھومنا طواف نہیں کہلا سکتا۔اس لیے اکادمی ادبیات کے چےئرمین فخر زمان صاحب نے اٹھائے گئے سوالات سے کنی کتراتے ہوئے اپنے ’’ابتدائی کلمات‘‘ میں صوفی ازم کی سیاست کاری (politicization) کو حرزِ جان بنائے رکھنے میں ہی عافیت جانی ہے:
’’ویسے تو صوفیوں کی تحریک قدیم ہے اور ہمیشہ سے موجود رہی ہے مثلاً بابا فریدؒ کو ہی لے لیں یا ان سے پہلے کے صوفیا کو دیکھ لیں۔ صوفیا کی یہ تحریک ایک خاص ڈھنگ اور چلن سے چلتی رہی ہے۔ اس تحریک کو آج کے عہد میں articulate کرنے، پھیلانے اور عوامی قومی اور عالمی سطحوں تک اس تحریک کی dissemination کی اشد ضرورت ہے تاکہ صوفیا کا پیغامِ محبت عام ہو۔ ......قومی یک جہتی ، مارشل لا ادوار کا رگیدا ہوا لفظ ہی نہیں، ہماری سلامتی کا ضامن بھی ہے۔ مگر قومی یک جہتی کسی طور پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ ہم چاروں صوبوں کے صوفیا کے سچے پیغام کے ابلاغ کے ذریعے اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔‘‘(ابتدائی کلمات:ص۲۶،۳۰)
کیونکہ صوفی ازم پر کانفرنس کا انعقاد ایک غیر سنجیدہ سرگرمی تھی بلکہ مذاق والی بات تھی، غالباً اسی لیے وزیر مملکت برائے تعلیم کو بھی اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ لیکن جناب غلام فرید کاٹھیا نے موضوع سے متعلق چند شستہ نکات اٹھا کر صوفیانہ کلام کی عصری معنویت ثابت کر کے ناقدین کے منہ بند کر دیے۔ لیجیے خود ہی دیکھ لیجیے:
’’اس دھرتی کے صوفی شاعروں نے درحقیقت اپنے وقت کے نظام کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیے رکھا۔ رحمان بابا کہتے ہیں:’’ظالم حکم رانوں کے سبب گور، آگ اور پشاور تینوں ایک ہیں‘‘۔ ہمارے ہاں فوجی جرنیلوں نے وہ کچھ کیا جس کا ذکر رحمان بابا کرتے ہیں۔ آج ذرا دیکھیے کہ پاکستان کے چاروں فوجی آمروں نے جو کچھ کیا، اس کے نتیجے میں آج رحمان بابا کا شعر کس قدر حقیقی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آج گور، آگ اور پشاور ایک ہو چکے ہیں۔‘‘(صوفی ازم کی عوامی بنیادیں:ص۳۲)
سردار آصف احمد علی صوفیانہ احوال کی ایک جہت سے کافی نالاں نظر آتے ہیں ۔ اس لیے گومگو میں تضاد بیانی کا شکار ہو گئے ہیں:
’’ مگر یہ توقع کرنا کہ صوفی، معاشرے میں انقلابی ریفارمر کا کردار ادا کرے یا جھنڈا پکڑ کر جہاد کرے یا اسلام دشمنوں کو نیست و نابود کرے تو تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مختلف اوقات میں اسی تجربے کے دوران کچھ لوگ انسپائر ہوئے اور انہوں نے جہاد بھی کیا، امام شمائلؒ کی مثال واضح ہے۔‘‘ (صوفی ازم:ص۳۸)
تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر بھی ہے اور پھر یہ بھی درست ہے کہ بتاتی بھی ہے، کیا طرفہ تماشا ہے؟۔ اس تماشے کے باطن میں کوئی صوفی جھانک سکتا ہے یا کوئی سردار ۔ جمع ضدین کے نجانے کتنے اور نمونے اس تلافی نامہ میں ہماری ضیافت کو موجود ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ سردار آصف احمد علی کے نام کے ساتھ اگر سردار نہ ہوتا تو کیا پھر بھی وہ ہم جیسے صوفیانہ مبتدیوں کو اس قسم کے’’ حکیمانہ ارشادات‘‘ سے نوازتے رہتے؟۔ یارو! ہمیں تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری اگر(خدا نخواستہ ) سردار آصف علی زرداری ہوتے تو ان کی گل افشانیاں سمیٹنے کی کوشش میں عوام کے ہاتھ پاؤں مسلسل پھولے رہتے۔ ویسے آپس کی بات ہے باریک بین حضرات، صدر آصف علی زرداری کے نام میں سردارمخذوف خیال کرتے ہیں ۔ شاید اسی لیے عوام بھی کچھ پھولے پھولے سے رہتے ہیں۔ خیر! اس جملہ معترضہ سے قطع نظر سردار آصف احمد علی لاعلمی میں ایک علمی بات کہ گئے ہیں، ملاحظہ کیجیے:
’’میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں روحانیت کا کوئی الگ سے سسٹم ہے۔ یہ کسی نظام کا نہیں، کسی فرد کا انفرادی تجربہ ہو سکتا ہے کہ اسے divine experience حاصل ہو۔ اس جدوجہد کے درمیان انسان کی جو tendencies ہیں، وہ سوشل ریفارمز کی طرف ہیں یا انقلاب کی طرف، جو بھی اس کے اندر جذبہ ہے اس کو تقویت ملے گی۔ ...... اگر کسی کی انسپائریشن کا حصہ جنگ لڑنا یا جہاد تھا تو اس نے روحانی تجربے کے بعد جنگ لڑی۔ کسی کی انسپائریشن شاعری تھی تو اس نے شاعری کی۔ صوفیانہ شعر کی روایت ہمارے ہاں خاصی مضبوط رہی ہے۔‘‘ (صوفی ازم:ص۳۷،۳۸)
یونی ورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد نظام الدین مخصوص عمرانی تناظر میں صوفیانہ روایت کی معنویت تلاش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ:
’’عوام زمین پر زمین کا سفر طے کرتے ہیں اور صوفی زمین سے آسمان کی جانب سفر کی راہ کھولتا ہے۔ بظاہر صوفی اور عوام دونوں کی منزلیں جدا جدا ہیں، تاہم زمین دونوں میں مشترک ہے اور یہی صوفی ازم کی عوامی بنیاد ہے۔ ......باریک بینی سے دیکھا جائے تو صوفی ازم کا اصل موضوع انسان اور عوام ہی تھا۔ کیونکہ انسان ہی سوال پوچھتا ہے اور انسان ہی ان کے جواب مانگتا ہے۔ ......زمانے نے جو گھاؤ نسل در نسل عوام کو دیے، ان پر اگر کسی نے مرہم رکھا تو وہ محض صوفیا ہی تھے۔ ...... صوفی فکر جو خاص طور پر شریعت کے میکانکی نفاذ سے ذرا ہٹ کر ہے اور عوام جو شریعت کی عملیت سے ذرا ہٹ کر ہیں، دونوں ایک غیر دانستہ اتحاد میں ہیں۔ ......مذہب تو پیغمبر لے کر آئے تھے اس کی ادارہ سازی علما نے کی تھی ان دونوں کے مقاصد پورے ہوئے کہ نہیں، مذہب کے سارے میکنزم سے صوفی کی وابستگی عوام کی سوچ کی حد تک سب سے زیادہ ہے۔ صوفیا ، لوگوں کے خیال میں مذہب کے سچے پیروکار ہیں، اس طرح سے لوگوں نے بھی صوفیا پر ایک جبر مسلط کیا ہے کہ وہ اسلام یا جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے، سے باہر نہ نکلیں۔‘‘ (صوفی ازم کی عوامی بنیادیں:ص۴۰،۴۱،۴۴،۴۵)
عوام اور صوفیا کے درمیان اشتراک و اختلاف کی نفسیاتی سرحدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں کہاں سے گزرتی ہیں اور کہاں ختم ہوتی ہیں، ڈاکٹر محمد نظام الدین ان پر کافی تیکھی نظر رکھے ہوئے ہیں:
’’اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ خدا کی ذات میں دخل حاصل کر سکے ہیں یا نہیں، مگر یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ عوام کی زندگی میں معتبر انداز میں داخل رہے ہیں۔ یہ اعزاز اتنے شان دار طریقے سے علما کو نہیں ملا جتنا صوفیا کو نصیب ہوا۔ ......عوام کو نفسیاتی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً محبت، امن، بھائی چارہ اور انسان دوستی۔ یہ سب کچھ انہیں ان ہستیوں میں نظر آتا ہے جو حکومتوں سے دور خدا سے لو لگائے بیٹھی ہیں، وہ خدا جس سے عوام کو بھی ساری آس امید تھی۔ یہ بھی صوفی اور عوام کی سانجھ تھی جو ہمیشہ قائم رہی۔ عوام نے کبھی صوفی ازم کی فلسفیانہ گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی نہ وہ انہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور صوفی کو عوام میں موجود سماجی آلودگیوں سے کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، وہ تو اپنی ذات کی تطہیر و پاکیزگی کی تلاش میں تھا، یہی وجہ تھی دونوں ایک دوسرے پر آشکار نہیں ہوئے۔ وہ ادراکی قربت پیدا نہیں ہوئی جو دوری کا باعث بنتی ہے، لہٰذا صوفی ازم اور عوام ہمیشہ اتحادی رہے۔‘‘ (صوفی ازم کی عوامی بنیادیں:ص۴۶،۴۷)
ڈاکٹر محمد نظام الدین صوفیا اور عوام کے درمیان اتحادِ محض کے داعی نہیں ہیں۔ وہ صوفیانہ واردات کے اس اظہار سے کافی الرجک دکھائی دیتے ہیں جو عوام کو سستانے اور سلانے میں منہمک رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بجا فرماتے ہیں :
’’اگر آج ہمیں صوفی ازم کے ان نظریات کو کسی سماجی ساخت میں ڈھالنا ہے تو ہمیں خود کو صوفی سے زیادہ انقلابی بنانا پڑے گا۔ ......صوفی ازم پر بہت زیادہ شور و غوغا مفاد پرستانہ لگتا ہے۔ یہ عوام کو گم راہ کرنے کا ایک ہتھیار بن سکتا ہے اور ان کی اس صلاحیت کو بھی جو انہوں نے democratization کے عمل میں حاصل کی ہے بے اثر کر دے گا جیسا کہ ہر status quo اپنے سامنے اٹھنے والے انقلابی نظریات کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمیں صوفیا سے اسی طرح inspiration لینی پڑے گی جیسی ہم اپنے سورما باپ دادوں سے لیتے ہیں چاہے وہ خود ہم نے ہی تخیلاتی طور پر بنائے ہوں یا حقیقت میں وہ نہتے اور کم زور لوگ ہی کیوں نہ ہوں اور ہر حکم ران اور حملہ آور کو خراج ہی دیتے رہے ہوں۔‘‘ (صوفی ازم کی عوامی بنیادیں:ص۴۷،۴۸)
پروفیسر نبیلہ کیانی نے مذہب کی ماہیت و مقصدیت سمجھے بغیر تصوف کی اضافی خوبیوں کی نشاندہی کی ہے۔ قارئین کی تفننِ طبع کے لیے ہم ایک اقتباس پیش کیے دیتے ہیں:
’’تصوف میں اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا صرف وہی نہیں ہے جس میں ہم اپنی سوچ کی مخصوص عادتوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں بلکہ اور بھی دنیائیں ہماری منتظر ہیں جہاں ہم اپنے thought pattern تبدیل کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ مذہب ہو یا تصوف، نئے modes of existence کا تصور دونوں میں موجود ہے۔ مگر دونوں میں فرق ہے کہ مذہب نے اگر اس existence کے علاوہ کسی اور mode of existence کی نشاندہی کی، تو ساتھ ہی اسے article of faith بنا کر مزید دنیاؤں کی تلاش پر پابندی لگا دی، جب کہ تصوف اور صوفیا کرام یہ تلاش جاری رکھنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ ...... صوفیانہ شاعری میں جن انسانی images کو معنویت حاصل ہے وہ ہیں Human beings at work ۔ ایک اور انسانی image جو شاعری میں نمایاں ہوتا ہے، وہ گیت گاتے اور رقص کرتے ہوئے انسان کا ہے۔ فن اور تخلیقِ فن اور تصوف کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔‘‘ (تصوف کی آفاقی قدریں:ص۵۲،۵۳)
پروفیسر نبیلہ کیانی اپنے اسی فن پارے میں معمولی تبدیلی کر کے ’’مذہب کی آفاقی قدریں‘‘ کے موضوع پر خامہ فرسائی کر سکتی ہیں۔ ویسے اس تبدیلی کے لیے پروفیسر ہونا ضروری نہیں، یہ تبدیلی کوئی معمولی کمپوزر بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اسے کرنا فقط یہ ہے کہ مذہب کی جگہ تصوف اور تصوف کی جگہ مذہب کا لفظ کمپوز کر دے۔ صاحبو! اگر کوئی سیمینار کانفرنس ’’مذہب کی عوامی بنیادیں‘‘ کے عنوان سے منعقد ہو تو پروفیسر نبیلہ کیانی کو ضرور خبر کر دیناکہ ان کا گھڑا گھڑایا مضمون کانفرنس میں قہقہے بکھیرنے کو تیار ہے۔ خیر سے پروفیسر خالد مسعود اسی کانفرنس میں تقدیمی قہقہے بکھیرنے کی کوشش میں ہیں:
’’جنرل پرویز مشرف کے روشن خیال دور میں ایک صوفی کونسل تشکیل دی گئی اور اس کونسل کے چیف صوفی کا درجہ جناب چوہدری شجاعت حسین کو عطا کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اس انتخاب کی وجہ دریافت کی، تصوف کی رمزوں سے آگاہ وہ دوست کہنے لگا کہ صوفی اپنا حال اور کیفیت دوسروں پر بیان نہیں کر سکتا، بس صوفی اور چوہدری شجاعت کے درمیان یہی ایک قدر مشترک ہے جس کی بنا پر انہیں چیف صوفی بنا دیا گیا ہے۔‘‘ (تصوف کی آفاقی قدریں:ص۶۵)
یہ درست ہے کہ جناب خالد مسعود بھی محترمہ نبیلہ کیانی کی طرح پروفیسر ہیں اور دونوں کا موضوع ’’تصوف کی آفاقی قدریں‘‘ بھی مشترک ہے، لیکن خالد صاحب نے برصغیر میں صوفیانہ سرمستیوں کی کارگزاری جلے کٹے انداز میں سنانے کے باوجود چند اصولی باتیں کی ہیں جن سے کوئی سلیم الفطرت شخص اختلاف نہیں کر سکتا:
’’ اگر بات صرف اور صرف تعلیمات پر عمل کر کے منزل کو پانے کی ہے تو یہ وصف صرف اور صرف قرآن و حدیث میں ہی ہے کہ آپ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ......صوفی، اپنی تعلیمات، گفتگو اور لفاظی سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور کردار سے متاثر کرتا ہے۔ اس کی ساری تعلیمات اس کا کردار اور عمل ہیں۔ ......اگر کسی کا خیال ہے کہ صوفیا کی تعلیمات صدیوں اور عشروں بعد بھی اسی طرح پیار محبت یگانگت بھائی چارہ تحمل اور رواداری عام کر سکتی ہیں جیسا کہ خود انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے عام کی تھیں تو یہ ایک مکمل خوش فہمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ‘‘ (تصوف کی آفاقی قدریں:ص۵۹)
پروفیسر خالد مسعود کا ایک فقرہ تو ’’سو سنار کی ایک لوہار کی‘‘ جیسے محاوروں کی صداقت کا زندہ جاوید نمونہ ہے، ملاحظہ کیجیے:
’’میں جب بھی اس سے اس سلسلے میں قرآن و حدیث کا حوالہ مانگتا ہوں، وہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابنِ عربی کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور سرمد کے اشعار سے بہلانے کی سعی کرتا ہے۔‘‘(تصوف کی آفاقی قدریں:ص۵۸)
ایک دور تک علامہ اقبال پر ’’پنجابی‘‘ ہونے کی پھبتی کسی جاتی رہی ہے اور ان کے نظریات کو ایک پنجابی مسلمان کی اسلام فہمی قرار دے کر ’’پنجابی اسلام‘‘ کی ترکیب چلانے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب قاضی جاوید صاحب نے اپنے موضوع سے ’’انصاف‘‘ کرتے ہوئے دل لگی کے انداز میں صوفی ازم کو خوب گلوبلائز کیا ہے:
’’اسلام جیسے عالم گیر مذہب کو پنجاب نے تصوف کا روپ دے کر گویا اس کو اپنی روح کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اس لحاظ سے تصوف، پنجابی اسلام تھا۔ ......اسلام کی اس پنجابی صورت کی تشکیل وحدت الوجود کی مابعد الطبیعات کے سبب ہوئی تھی جو پانچ ہزار سال سے پنجابی روح کا بنیادی عنصر ہے۔‘‘(گلوبلائزیشن اور صوفی ازم:ص۶۸)
پروفیسر حمیدہ شاہین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ان کے مخاطبین پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کی غالب اکثریت کا مذہب اسلام ہے، اس لیے ان کی نظریں صوفیانہ روایت کے اسلامی ایڈیشن تک ’’محدود‘‘ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں:
’’صوفیا نے سلوک کی جو منازل بعد میں متعین کیں وہ اسلام کے دورِ اول میں اپنی فطری اور حقیقی صورت میں موجود تھیں اور ان پر چلنا اس ماحول میں چنداں دشوار نہ تھا۔ شریعت ، طریقت ، معرفت اور حقیقت کے مرحلے روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ تصوف نے اس دور میں انسان کے فطری تقاضوں کو چھیڑے بغیر عوام سے خطاب کیا اگرچہ اس کو تصوف کا نام بھی بعد میں دیا گیا۔ ......کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دینِ اسلام سے باطنیت کا گودا نکال کر الگ کر دیا گیا اور بے رس بے ذائقہ چھلکا مولوی کے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ جاؤ لوگوں کو بے روح نمازوں اور بے حضور سجدوں میں مشغول کر دو۔ ان الصلوۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر پر غور کرنے کی فرصت نہ ملے تو کوئی بات نہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے آئی تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ دوسری طرف بے شرع تصوف کا ڈول ڈالا گیا۔ عالمِ استغراق میں رفع وجوب کی پٹی پڑھا دی گئی اور یوں جذب و مستی پیدا کرنے کے جعلی و خارجی طریقے خانقاہی زندگی کا حصہ بنا دیے گئے۔‘‘ (تصوف ۔ دین عوام یا دین خواص: ص ۹۹، ۱۰۳، ۱۰۴)
پروفیسر حمیدہ شاہین نے صوفی کو خاص انسان قرار دیتے ہوئے ان سمتوں کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے جو عام آدمی اور صوفی کے درمیان خطِ تفریق کھینچ دیتی ہیں:
’’عوام فقط بصارت ہیں، خواص بصیرت بھی ہیں۔ عام آدمی زمین پر چلتا ہے، خاص انسان زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ زمین سے آسمان بہت دور دکھائی دیتا ہے، اس لیے عام آدمی نے تصوف کے معاملہ میں اپنے مقام کو آسانی سے قبول کر لیا۔ ......صوفیا کے تذکرے بتاتے ہیں کہ خواص کی نظر مقصودِ اصلی پر اور عوام کی نظر خواص پر ہوتی ہے۔ صوفی کسی اور مرکز کے گرد گھومتا ہے ، عوام صوفی کے گرد گھومتے ہیں۔‘‘ (تصوف ۔ دین عوام یا دین خواص:ص۹۲،۹۳)
پروفیسر صاحبہ کو صوفیانہ واردات کی اظہاری گنجلک کا بھر پور احساس ہے۔ اس لیے انسانی زندگی میں روحانی تجربات اور تصوف کی اہمیت سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے ابلاغ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ:
’’اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم کے سائے میں بیٹھے ہوئے انسان کو یہ بات صرف تصوف ہی بتا سکتا ہے کہ شاخِ بدن پر ابدیت کے پھول نہیں کھلتے، لیکن یہ بتانے کے لیے تصوف کو وہ زبان اختیار کرنی پڑے گی جسے عام آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔‘‘(تصوف ۔ دین عوام یا دین خواص:ص۱۰۵)
اس سلسلے میں سچ یہ ہے کہ تصوف زبان و بیان نہیں بلکہ کردار و عمل سے عبارت ہے۔ اس لیے زبان کی سلاست تلاشنے کے بجائے پروفیسر صاحبہ کو آتشِ رفتہ کا سراغ لگانا چاہیے۔ البتہ جیلانی کامران کے حوالے سے انہوں نے جو نکتہ اٹھایا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ:
’’تصوف اور معاشرہ صرف ایسے موسم میں قریب آتے ہیں جسے غزل کی اصطلاح میں عشق کا موسم کہتے ہیں۔ جب سے تصوف کا رشتہ معاشرے کے ساتھ منقطع ہوا ہے زندگی محبت کی زبان میں بات کرنا بھول گئی ہے۔‘‘(تصوف ۔ دین عوام یا دین خواص:ص۱۰۵)
پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید بھی عشق کے موسم کی راہ دیکھتے ہوئے صوفی، ترکِ دنیا اور معاشرہ کے داخلی توازن کی بابت فرماتے ہیں کہ:
’’صوفی کا فقر اسے ترکِ دنیا کا درس نہیں دیتا بلکہ اسے معاشرے کے ایسے فرد کا درجہ عطا کرتا ہے جو انسانی اصلاح پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ اس کی بدولت سماجی زندگی کو حیوانی جبلتوں کے دائروں سے باہر رکھا جا سکے۔ ......اگر غور سے اور تعصب کی پٹی اتار کر صوفیانہ بیانات کی روح کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا کو ترک کرنے کے لیے کہتے ہیں جو خدا کے راستے میں حائل ہوتی ہے نہ کہ راہبوں کی طرح دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا ان کا مقصود ہے۔‘‘(تصوف، شہنشاہیت اور انسانی توقیر:ص۱۱۴،۱۱۶)
ڈاکٹر سعادت سعید صاحب نے صوفی اور وراثتی صوفی کی تفریق قائم کر کے تصوف کی لاج رکھنے کی لائق تحسین کوشش کی ہے۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ:
’’صوفیوں کی گدیوں پر بیٹھے غیر صوفیوں یا وراثتی صوفیوں نے ۱۸۵۷ کی ہندوستانی جنگِ آزادی میں انگریزوں کے اتحادی بن کر جو ’’کارہائے نمایاں‘‘ انجام دیے ہیں اس سے ہماری تاریخ کے وہ صفحات بھرے ہوئے ہیں جن کے گرد سیہ حاشیے لگنے چاہئییں تھے۔‘‘(تصوف، شہنشاہیت اور انسانی توقیر:ص۱۱۰)
پروفیسر سعادت سعید صاحب صوفی کے سماجی کردار کو کلیدی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے صوفی کے سیاسی کردار کی تحدید ان الفاظ میں کی ہے:
’’صوفی، شہنشاہوں کے غیر انسانی رویوں اور مظالم کے خلاف علامتی، تمثیلی، استعاراتی پیراؤں میں اظہارِ خیال کرنے سے نہیں چوکتے تھے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ بادشاہت کے ادارے کو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو ایسا نہیں تھا۔‘‘(تصوف، شہنشاہیت اور انسانی توقیر:ص۱۱۸)
زیرِ نظر تلافی نامہ کے بیشتر مضامین مخمل میں ٹاٹ کا پیوند معلوم ہوتے ہیں لیکن پروفیسر سید شبیر حسین شاہ کا مضمون ٹاٹ میں مخمل کا پیوند دکھائی دیتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے:
’’دونوں قسم کے لوگ یعنی علما اور صوفی پہلے سے موجود ایک فکری نظام کی سرحدوں کے اندر کارندوں کی طرح کام کرتے ہیں، کبھی بھی جبر و استبداد کی قوتوں کو ان سے بڑا خطرہ نہیں رہتا اور یہ سماج کی اندرونی ساخت اور حرکت میں خارجی عوامل کی طرح سے موجود رہتے ہیں، جب کہ اشتراکیت اپنی حکمت اور علمی ساخت میں سماج کی اندرونی پرتوں کے ضمن میں ایک جنگجویانہ لائحہ عمل رکھتی ہے۔ اس کی ساری inspiration آسمانوں سے نہیں اترتی، بلکہ معروض میں موجود قوتوں کے جدل سے پیدا ہوتی ہے۔ اشتراکیت اپنے عہد کے سماجی نظم میں سب کے لیے قابلِ قبول نہیں ہے۔ تصوف لاشعوری طور پر خدا کے اندر داخل ہونے کی جہدِ مسلسل میں ہے۔ اشتراکی، انسان کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفی زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے despotic حکم رانوں کو مہذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عالمِ دین بھی یہی کام کرتا ہے۔ ظالم اجارہ دار حکم رانوں انسانوں سے پیار و محبت کا درس ہے تو بڑا خوب صورت، مگر ہے انتہائی منافقانہ۔ وہ جس نے تلواروں کی طاقت سے شاہی ہتھیائی ہو، اس کے استحقاق کو چیلنج کیے بغیر انسانوں کی رعیت کے لیے اس سے مراعات کی جدوجہد کرنا درحقیقت اس کے کارندے کے طور پر کام کرنا ہے۔‘‘(اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص۱۲۷،۱۲۸)
وحدت الوجود کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے ہوئے شبیر صاحب نے محبت کی اشتراکی اساس کا کھوج خوب لگایا ہے:
’’صوفی یہ وضاحت نہیں کرتا کہ وہ خدا کے وجود میں پیوست ہو کر کن مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ وحدت الوجود کی direction بندے سے خدا کی طرف سفر ہے مگر اپنی نفسی ساخت میں خدا کو بندے میں حلول کرنے کا عمل ہے۔ دونوں صورتوں میں بندے کی بندوں سے شراکت کو کوئی بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ بندوں کی بندوں سے محبت کا نظریہ بھی محض ایک یاوہ گوئی اور بندوں کے مابین تفریق سے چشم پوشی اور انحراف ہے۔ محبت ایک end سے جاری ہونے والی مافوق الفطرت شے نہیں ہے جو انسانوں کو اپنی جکڑ بندی میں لے لے گی، بلکہ یہ انسانی سانجھ اور مشترکہ تحرک کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذہنی قبولیت اور نفسیاتی سانجھ ہے جس کا براہ راست تعلق social activism سے ہے۔ اور پھر صوفی جس قبیل کی محبت کا داعی ہے وہ دست برداری یا بے عملی سے پیدا ہوتی ہے یا ایک investment کے طور پر۔‘‘(اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص۱۲۹)
اب ملاحظہ کیجیے کہ صوفی اور اشتراکی نے خلیفہ بننے سے کیسے انکار کیا۔ سمتوں کے فرق کے باوجود انکار دونوں جگہ پایا جاتا ہے، لیکن گردن زدنی بے چارہ اشتراکی قرار پاتا ہے:
’’اشتراکیت اپنی حد بندی کرنے میں اپنے جدید ہونے کی دعوے دار ہے۔ اس کا سارا انحصار انسانوں کے ان تجربات پر ہے جو انہوں نے نسلِ انسانی کے ارتقا میں حاصل کیے۔ یہ تجربات درحقیقت معروض کے ساتھ انسانوں کے interaction کا نام ہے۔ اسے آسمانوں نے کوئی راہنمائی نہیں ملی کہ انسان کبھی بھی ظلِ الٰہی نہ تھا۔ مذہب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ خلیفۃالارض ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس خلیفہ کے پاس اختیار کی ملکیت کس کی تھی، اگر وہ خدا کی تھی تو پھر اختیارات میں موجود سارے امتیازات بھی خدا کی طرف سے تھے۔ اشتراکی نے بڑی ڈھٹائی سے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس نے اپنے معروض کو اپنی مرضی سے بدلنے کا نظریہ اختیار کر لیا۔ یہ مذہب پرستوں کے نزدیک خدائی کاموں میں مداخلت تھی۔ مگر جب صوفی نے اپنے انسانی وجود کی نفی کی اور اپنے خلیفہ ہونے کو خود خدائی وجود کا پرتو قرار دیا، تو دراصل اس نے بھی خلیفہ بننے کی نفی کر دی۔
صوفی کے سامنے ideal پیغمبری تھی۔ وہ اپنے اعلی ترین درجے میں وہ کمال حاصل کر لیتا ہے کہ پیغمبری بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پیغمبری تو روح القدس یا جبریل کی محتاج رہتی ہے۔ صوفی براہ راست اللہ تعالی سے القا حاصل کرتا ہے اور خدا کے رازوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ وہ خلیفۃالارض کی ادنی حیثیت سے خود کو بہت دور لے جاتا ہے۔ خلیفۃ الارض یا انسان جب اپنے اختیارات سے دست بردار ہوتا ہے اور اپنی دانست میں دنیاوی آلودگی سے خود کو پاک کرتا ہے تو وہ ایک سمت میں چلتا ہے۔ مگر جب وہ مزید اختیارات مانگتا ہے، دنیا کی تمام آلودگیوں کے اندر بیٹھ کر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ دوسری سمت میں چلتا ہے۔ سمتوں کا یہ فرق بھی صوفی اور اشتراکیت کا فرق ہے۔‘‘(اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص۱۳۰،۱۳۱)
پروفیسر شبیر صاحب نے صوفی کے ممتاز ہونے کی وجوہ پر ایسی چوٹ کی ہے کہ کسی ملامتی کو بھی کہیں پناہ ملتی نظر نہیں آتی:
’’صوفی اپنی خواہشات کو تیاگ کر دوسرے انسانوں میں خود کو ممتاز کرتا ہے اور اپنے سے والہانہ قبولیت پیدا کرتا ہے۔ اشتراکی دوسروں کی خواہشات کو ابھار کر ایک عملی اشتراک حاصل کرنا چاہتا ہے، اس طرح خود کو انسانوں میں لازم و ملزوم بناتا ہے۔صوفی کے ٹارگٹ اس کی اپنی imagination اور intuition سے بنتے ہیں۔ اشتراکی کے ٹارگٹ پہلے سے زمین پر موجود ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنی علمی صلاحیت سے conceive کرتا ہے۔ اسے معروض سے فرار کا حق حاصل نہیں ہے۔ مادے کی جدلیات بظاہر انسان کے خارج میں موجود ایک کائناتی عمل ہے، مگر درحقیقت خود انسان اسی جدلیات کے ایک عنصر کے طور پر موجود ہے، اور اشتراکی کو اس کا ادراک ہونا چاہیے ورنہ وہ اپنی حکمتِ عملی ترتیب نہیں دے سکتا۔‘‘(اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص۱۳۱)
شبیر حسین صاحب نے کوئے یارسے نکلے صوفی کے ’’فنا‘‘ ہونے کو معاف نہیں کیا۔ اس لیے گمان یہی ہے کہ وہ سوائے دار چلے خود کش حملہ آوروں کی معافی کے بھی قائل نہیں ہوں گے:
’’بدی کو دھتکارنے کا سارا وجدان اور ریاضت کا عمل صوفی کو اس کے مقدر میں ملا ہے۔ اشتراکی کا مقدر اس کے عہد کی ناقابلِ تردید زمینی حقیقت ہے اور یہ حقیقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ utopia کبھی معرضِ وجود میں نہیں آتا۔ اعلیٰ درجے کا کمیونسٹ معاشرہ ایک حقیقت سے زیادہ ایک inspiration ہے جو اشتراکی کو ایک علمی فرد سے انقلابی میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ انقلابی بننے کے لیے عوام سے اپنی جڑت کا محتاج ہے، لہذا اشتراکی کو خدا کی ذات سے زیادہ بندوں کی ذات پر غور کرنا پڑتا ہے۔ ......اشتراکی، زندگی کا صوفی سے بہتر آرگنائزر ہوتا ہے وہ زندگی کو ایک اثاثے کے طور پر اپنی جدوجہد میں استعمال کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو پر حاوی رہتا ہے۔ صوفی پر زندگی کا تاریک حصہ ایک بوجھ ہے، جسے اتارتے اتارتے اس کی زندگی کا روشن پہلو بھی فنا ہو جاتا ہے اور اسی فنا میں صوفی سدا کی زندگی پاتا ہے۔‘‘(اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص۱۳۱،۱۳۲)
سطورِ ذیل میں شبیر صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی نے بے چارے صوفی کو ہمیشہ مار پڑوائی ہے۔ ہم گزارش کریں گے کہ صوفی بے چارہ اس وقت تو ایک اشتراکی کے ہتھے چڑھا ہوا ہے اور اس کی وہ درگت بن رہی ہے کہ وہ مولوی کی مار بھولے سے بھی یاد نہیں کرے گا :
’’تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا اشتراکی کا انکار گردن زدنی ہوتا ہے، صوفی کو اتنی مار نہیں پڑتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آمرانہ ملوکیتوں نے خود اپنی سوچ سے صوفی دشمن پالیسی اپنائی یا ہمیشہ interpretation کی آڑ لے کر وقت کے مولوی نے صوفی کو مار پڑوائی۔ جیسے عیسٰی مسیح علیہ السلام کو فریسی یہودیوں نے صلیب پر لٹکوا دیا تھا۔ اشتراکی کی لڑائی حاکمیت سے براہ راست ہوتی ہے، اس لڑائی سے فرار ممکن نہیں، ورنہ اشتراکی اپنی وجودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ صوفی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمیں کبھی کبھی حکم رانوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، جب کبھی وہ عوام کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کسی جنگ کا آغاز نہیں کرتا، اس کی ساری ترغیب غیر جدلیاتی غیر سائنسی اور بے سمت ہوتی ہے۔ جب انقلاب، تاریخ کے ایجنڈے پر نہیں ہوتا تو انسانوں کے قول و فعل پر صوفی کا راج ہوتا ہے، بلکہ صرف قول پر، فعل تو شاہوں کی لونڈی ہوتا ہے۔ دونوں مل کر انسان کو اس کی اسی حالت میں برقرار رکھتے ہیں۔ بادشاہ اس کی زندگی کو عذاب بناتا ہے، صوفی اس کی زندگی کو خیالی جنت بناتا ہے۔ دونوں میں آخر لڑائی کہاں ہے۔‘‘ (اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص ۱۳۳)
صوفی کے وہم اور اشتراکی کی سرفرازی کی تحلیل شبیر صاحب نے کچھ اس طرح کی ہے:
’’جس طرح تہذیب دورِ وحشت کی آغوش میں جنم لیتی ہے اور اتنی ہی باصلاحیت ہوتی ہے جتنا دورِ وحشت کا انسان اپنی بقا کی جنگ میں طاقت حاصل کرتا ہے۔ potential ایک مادی وجود کا نام ہے جو انسانی زندگی اور معاشرت میں قوتِ محرکہ کا کام کرتا ہے۔ صوفی کا علمی وجدان بھی اس کے اندر ایک potential پیدا کرتا ہے جس کے بل بوتے پر صوفی میں انسانی صلاحیت اپنے کمال سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ یہیں پر صوفی اس واہمہ کا شکار ہوتا ہے جو اسے الوہی ماہیت میں خلط ملط کر دیتا ہے۔ جب کہ اشتراکی اپنے عمیق علمی تجزیے میں کائنات کی سچائیوں سے سرفراز ہوتا ہے اور ایک potential حاصل کرتا ہے۔ یہ صلاحیت اسے آسمانوں کے بجائے سماج کی تہوں میں لے کر اترتی ہے اور اشتراکی اپنے کمال کے ساتھ انسانوں سے خلط ملط ہو جاتا ہے جہاں سے انقلاب کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ یہ روشنی لازماً اس نور سے مختلف چیز ہے جو صوفی کے دل میں اترتا ہے لوگ جس کے متلاشی رہتے ہیں۔ مگر اشتراکی کو لوگوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے، یہاں activity اور inactivity کا فرق ہے۔‘‘ (اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات: ص ۱۳۳، ۱۳۴)
سید شبیر حسین صاحب اپنے نتائجِ فکر میں صوفی اور اشتراکی میں کوئی اشتراک نہیں دیکھ پاتے۔ اس لیے وہ فیصلہ کن انداز میں لوگوں سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں:
’’چونکہ آسمانوں سے کوئی تبدیلی زمین پر نہیں اترتی، لہٰذا جب صوفی خدا سے ملاپ کر کے واپس اترتا ہے تو کسی تبدیلی پیدا کرنے کے اہل نہیں ہوتا ۔ اس لیے صوفی سے عامۃ الناس کی relationing ایک سعی لاحاصل ہے۔ انہیں اشتراکی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یا کہیں اور جانا پڑے گا۔ جب کوئی چیز surface پر موجود نہیں ہوتی تو محض تصوریت ہوتی ہے۔ چاہے اشتراکیت ہو، چاہے صوفی ازم، جب تک حالت بے عملی میں ہیں زبردست اشتراکات میں ہوتے ہیں۔ جب حرکتِ عمل میں جاتے ہیں، الٹ سمتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لہذا انسانی فلاح کے لے صوفی اور اشتراکی میں اشتراک ممکن نہیں ہے اور لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہو گا کہ وہ کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اگر صوفی کے ساتھ جائیں گے تو اپنے دکھوں کا مداوا آسمانوں سے طلب کریں گے، حاکموں ا8 ور اجارہ داروں سے تعرض نہیں کریں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے جبر و استبداد کو بری الذمہ کرنے کا۔ تنخواہ دار مولوی سرکاری ادیب اور دنیا سے لاتعلق صوفی سب یہی کام کرتے ہیں۔‘‘ (اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص۱۳۴)
شبیر صاحب کی نظر سے صوفی اور اشتراکی کا نقطہ اتصال چھپ نہیں سکا۔ وہ ایک معروضیت پسند اشتراکی ہیں۔ اس لیے انہوں نے تحفظات کا شکار ہوئے بغیر اس مماثلت کو معروضی انداز میں تسلیم کیا ہے:
’’یہاں ایک سوال اشتراکی کے ضمن میں بھی بڑا اہم ہے کہ اگر اشتراکیت کا مرحلہ برپا ہو جاتا ہے اور اقتدار پرولتاری ڈکٹیٹر شپ سے ایک non-state سوسائٹی کے ہاتھ چلا جاتا ہے اور مارکسی انقلاب اپنی اعلیٰ منزل سے سرفراز ہوتا ہے، تو کیا اشتراکی اپنے انفرادی وجود سے دست بردار ہوجاتا ہے جس طرح صوفی خدا میں مدغم ہو کر اپنے وجود سے دست بردار ہو جاتا ہے۔ اپنے عروج کی اس مکینکس میں جو اشتراک پایا جاتا ہے بھلے وہ نوعیت اور ساخت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے مگر اپنے رجحان میں یہ صوفی اور اشتراکی کا واحداشتراک ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ صوفی اور اشتراکی حتمی طور پر جس جہدِ مسلسل میں ہیں وہ دراصل اپنے وجود کو کسی اور وجود میں ڈھالنے کی جدوجہد ہے، یعنی اب ہم صرف technicalities اور نظریاتی سمتوں پر ہی تضاد دیکھتے ہیں۔
مارکسیوں نے جب مادے کی حرکت کے قانون کو سماج کی حرکت پر منطبق کیا تھا تو ان کے پاس چارہ نہیں تھا کہ سماجی حرکت کو مادے کے قانونِ حرکت کے تحت لے کر آئیں اور وہ حکمتِ عملی تشکیل دیں جو سماج کے اندر کی تشکیل بندی کو مادے کی جدلیاتی سائنس کے قانون کے تحت کریں۔ اپنی دانست میں وہ یہاں social scientist ٹھہرے اور بلا شبہ وہ تھے، مگر جب صوفی نے یہ نعرہ لگایا کہ خدا نے اپنے اندر ایک قانونِ فطرت قائم کر رکھا ہے اور وہ انسان کی تخلیق اپنی ہی فطرت اپنے ہی وجود کی حدود میں سے کرتا ہے اور انسان اسی کا حصہ رہتا ہے، لہذا نسان پر جب صوفی، خدا کے اندر کی فطرت کا نفاذ چاہتا ہے تو دراصل صوفی انفرادی طور پر وہی کام کرتا ہے جو اشتراکی اجتماعی طور پر کرنا چاہتا ہے۔ اشتراکیت اور صوفی ازم تقریباً ایک ہی جیسے انسان کو اپنا آلہ کار بناتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے وجود اور تشخص کو آسمانوں پر ان دیکھے خدا کی سپردگی میں دینا ہے یا لاکھوں کروڑوں استحصال زدہ لوگوں کاسر اٹھا کر انہیں سر بلند کرنا ہے۔ یہ کام صوفی ازم اور اشتراکیت میں اشتراکات تلاش کرنے سے نہیں ہو گا بلکہ عوام تک یہ شعور لے جانے سے ہو گا کہ وہ حقیقتوں کی طرف پلٹ آئیں۔‘‘(اشتراکیت اور صوفی ازم کے اشتراکات:ص ۱۳۴، ۱۳۵)
سید شبیر حسین شاہ کے مضمون کے مذکورہ اقتباسات کی مجموعی معنویت ملحوظ رکھتے ہوئے ہم گزارش کریں گے کہ سامراج نے مذہب کی اہمیت بھانپتے ہوئے اسے ہمیشہ ہائی جیک کیا ہے اسی لیے مذہب عوام کے لیے افیون قرار پایا ہے۔ لیکن نام نہاد معروض پسندوں نے معروض میں موجود مذہب کی مکمل نفی کرتے ہوئے (سامراج کو کھلی چھٹی دے کر) جدلیات کو عملی طور پر ہمیشہ بے معنی ثابت کیا ہے۔ لہذا حقیقی معروض پسند تو سامراجی ٹھہرے نہ کہ ہمارے اشتراکی بھائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شبیر صاحب کے اس مضمون سے مذہب(خاص طور پر اسلام) کی بے عمل تعبیر کرنے والے اجارہ داروں کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا چاہیے جنہوں نے دین اسلام کے پیروکاروں کو مستقل سراسیمگی میں مبتلا کر رکھا ہے:
رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خور است
نہ کشتی اندراں دریا نہ ملاحے عجب کار است
(میں اس دریا میں پہنچا ہوں کہ جس کی موجیں آدم خور ہیں، دریا میں نہ کشتی ہے اور نہ ملاح، عجیب ماجرا ہے)
خیر! پروفیسر نصر اللہ خان ناصر نے سرپٹ دوڑتے تاجرانہ گھوڑے کو روحانی لگامیں ڈالنے کی بات چلائی ہے۔ انہوں نے سید شبیر صاحب کے برعکس سرمایہ دارانہ معیشت میں صوفیانہ کردار کی راہ ڈھونڈ نکالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ صارف معاشرہ صوفیا کے لیے بھی اصولی طور پر قابلِ قبول نہیں ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ:
’’ہر رویے اور رشتے کو مفادات کے ترازو میں تولنے کی روش اور تاجرانہ وطیرہ ہماری سماجی زندگی اور اخلاقی اقدار میں فطری توازن کی نفی کر رہا ہے۔ یہی معاشرتی تقاضوں کا تضاد ہمارے اندر وہ تناؤ پیدا کرتا ہے جو ہمارے اذہان و قلوب کو بے چارگی، بے بسی، حسد اور محض دنیاوی آسائشوں تک رسائی کی تحریک دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں عورت کا حسن و جمال، مرد کی مردانہ وجاہت، مردانگی کا وقار، بچوں کی معصوم مسکراہٹ اور کلکاریاں اور ممتا کے لازوال جذبوں کو اس نے اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کے لیے اشتہارات کی زینت بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے ترازو کے پلڑے میں بکنے کے لیے رکھ دیاہے۔ ہمارا صارف معاشرہ مکمل طور پر انسان کو بکنے اور خریدی جانے والی اشیا کی فہرست میں شامل دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی اس عہد کا سب سے بڑا المیہ ہے اور اسی المیے کی اثر پذیری اور فعالیت پوری انسانیت کے لیے ایک سنگین خطرے کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جس کا تدارک ہماری اپنی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر صوفیا کے نزدیک چونکہ انسان ہی مقصود بالذات ہے اس لیے وہ اس صارف کلچر صارف اپروچ اور عہدِ حاضر کی صارفی معیشت کے تقاضوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ معیشت طبقات پیدا کرتی ہے طبقاتی تضادات کو تقویت دیتی ہے، اس لیے صوفی اس طبقاتی معیشت کی بھر پور نفی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے بعض صوفی شعرا کے کلام میں مادی جدلیت کی طرف جگہ جگہ واضح اشارے ملتے ہیں۔‘‘(صوفی ازم اور صارف معاشرہ: ص ۱۴۳، ۱۴۴)
سید شبیر صاحب کو صوفی کے فنا ہونے پر اعتراض تھا، لیکن ڈاکٹر محسن مگھیانہ اس فنائیت میں پناہ ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ دونوں حضرات معروض پسند ہیں اور معروض پسندوں کی تعبیرات میں اصولاً یکسانیت ہونی چاہیے، جو یہاں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے، ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اس ’’تلافی نامہ‘‘ میں جہاں جہاں مطلوبہ یکسانیت سے روگردانی کی گئی ہے اس کی تلافی کے لیے ایک اور تلافی نامہ بہت جلد منظرِ عام پر آئے گا۔ ڈاکٹر محسن کے الفاظ ملاحظہ کیجیے:
’’سارے جھگڑے ہی اپنی حاکمیت جتانے کے ہیں، دنیا پر قبضہ کرنے کے ہیں، چاہے وہ محلے، شہر، صوبے یا ملک کی حاکمیت ہویا پھر ساری دنیا کی۔ دنیا سے حب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کی فنا کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ صوفی کو دنیا سے اس لیے رغبت نہیں رہتی کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے فنا ہو کر بالآخر اسی ذات میں واپس جانا ہے جس کا ہم ایک ٹکڑا تھے اور جسے وقتی طور پر زمین پر بھیجا گیا تھا۔‘‘(کنزیومر ازم کے دور میں صوفی ازم کی اہمیت:ص۱۵۷)
ڈاکٹر محسن صاحب نے منصور حلاج کے ’’اناالحق‘‘ کی بابت ڈاکٹر نکلسن کے درج ذیل الفاظ نقل کر کے اپنے تئیں علمی وجاہت کا ثبوت فراہم کیا ہے:
’’حلاج کے انالحق کا مطلب یہ نہ تھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ یہ تھا کہ میں حق یعنی سچ creative truth ہوں۔ یہ نظریہ ہمہ اوست pantheism کے سراسر خلاف ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان خدا کا مظہر ہے۔ یہ نظریہ حضرت عیسیٰؑ کے ان کلمات کے تقریباً مطابق ہے جس میں آپؑ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا باپ (خدا) کو دیکھا۔ لیکن یہ نظریہ جسے حلول incarnation سے موسوم کیا جاتا ہے، اسلام میں جڑ نہ پکڑ سکا۔ اسے حلاج اور ان کے مریدوں نے ہی ختم کر دیا تھا۔ صوفیا کہتے ہیں کہ حلاج کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا کہ وہ ’’حلولی‘‘ تھے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا۔‘‘(کنزیومر ازم کے دور میں صوفی ازم کی اہمیت:ص۱۵۴)
صاحبو! ہم کب پیچھے رہنے والے ہیں، علمی وجاہت نہ سہی، لاعلمی سہی، ثبوت تو ہم بھی فراہم کرنے سے نہیں چوکیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ حسین ابن منصور کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، مگر وہ مسکراتے رہے اور ان کی ہر انگلی سے (دروغ بر گردنِ راوی) اناالحق کی صدا آتی رہی۔ انہیں دار پر کھینچا گیا تب بھی اناالحق پکارتے رہے۔ جلا دیا گیا تو راکھ کا ہر ذرہ اناالحق کی صدا بن گیا۔ تین دن بعد راکھ کو دریا برد کیا گیا تو وہاں بھی اناالحق کا آوازہ گونجتا رہا۔ دوستو! یہ سب اس لیے ہوا کہ حسین ابن منصور توحیدِ رسمی پر اکتفا کرنے کے بجائے توحیدِ حالی سے سرفراز ہوئے تھے، وگرنہ نجانے کتنے ارب انسانوں کی راکھ گنگا جمنا میں بہائی جا چکی ہے لیکن وہاں کبھی اناالحق کا آوازہ سنائی نہیں دیا۔ خیر! ڈاکٹر محسن مگھیانہ نے سلطان باہوؒ کے پنجابی کلام پر اپنی بات ختم کی ہے:
’’ اگر رب نہانے دھونے اور صاف ستھرے رہنے سے ملتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو مل جاتا۔ اگر لمبے بال رکھنے سے مل جاتا تو بھیڑوں بکریوں کو مل جاتا۔ اگر رب کا دیدار رات بھر جاگنے اور پرندوں کی طرح کوکنے سے ملتا تو ان پرندوں کال کڑچھیوں کو مل جاتا جو ساری رات جاگتے اور شور مچاتے ہیں۔ اگر رب محض مجرد رہنے والوں کو ملنا ہوتا تو قوتِ تولید سے محروم بیلوں مل جاتا۔ لیکن اصل بات تو باہو یہی ہے کہ ان باتوں سے رب حاصل نہیں ہوتا بلکہ انہیں ملتا ہے جو دل کے اچھے اور من کے سچے ہوں جن کی نیت صاف ہو۔‘‘ (کنزیومر ازم کے دور میں صوفی ازم کی اہمیت:ص۱۵۸)
اکادمی ادبیات کے چےئر مین فخر زمان صاحب نے اختتامی کلمات میں خیر کے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے انہیں قارئین کے سامنے ’’تبرکاً‘‘ پیش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ موجود نہیں:
’’ہر شخص کے اندر ایک صوفی ہوتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خیر ہے وہ کہیں شر کے ہاتھوں برباد تو نہیں ہو گیا۔ اس خیر کو بچانے، زندہ اور متحرک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ......صوفی ازم بے عملی نہیں بلکہ شر کے مقابلے میں حرکتِ خیر کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ صوفیوں میں بے عملی بھی رہی ہو مگر میرا خیال ہے کہ حقیقت میں کوئی صوفی بے عمل نہیں رہا۔ اگر صوفی بے عمل ہوتے تو سرمد اور منصور کو قتل نہ کیا جاتا، انہوں نے اسٹیبلیشمنٹ کو پکارا اور للکارا، تبھی تو سزاوار ٹھہرے۔ اگر صوفی محض بے عمل ہوتے تو ملائیت بلھے شاہ کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہ کرتی۔ ......ہمارے صوفیوں نے تو ہمیشہ بغاوت کی ہے اور بغاوت کے لیے ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کوئی حرفِ انکار سے بغاوت کرتا ہے، کوئی لفظوں کو ہتھیار بناتا ہے، کوئی عمل سے بغاوت کرتا ہے اور بندوق اٹھا لیتا ہے۔‘‘ (اختتامی کلمات:ص۱۶۵،۱۶۶)
اب ہم بھی اختتامی کلمات کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن آغاز کے مانند پھر ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ کوئی اشتراکی خواب بھی دیکھ سکتا ہے:
’’مثالی انسانی معاشرے کی تشکیل خوابوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم اچھے خواب نہیں دیکھیں گے، اچھے اعمال ہم سے سرزد نہیں ہو پائیں گے۔‘‘(اختتامی کلمات:ص۱۶۸)
فخر صاحب نے شبیر صاحب جیسے اشتراکی بھائیوں کو ایک بڑی مشکل میں پھانس دیا ہے، وہ بھلا خواب کی مادی جدلیاتی توجیہ کیسے کر پائیں گے؟کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا!
توہین رسالت کے مرتکب کے لیے توبہ کا موقع ۔ حدیث اور فقہ کی روشنی میں
مفتی محمد عیسی گورمانی
(توہین رسالت کی سزا کے قانون کے حوالے سے علمی حلقوں میں جاری بحث ومباحثہ میں یہ پہلو خصوصی طور پر ارباب فکر ودانش کے درمیان زیر بحث ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کے لیے توبہ اورمعافی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ ہمارے مخدوم ومحترم بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی مدظلہ العالی نے اس پر اپنا موقف بیان فرمایا ہے جو ارباب علم ودانش کی خصوصی توجہ کا طلب گار ہے۔ اس پر کوئی دوست خالص علمی انداز میں اظہار خیال کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس کے لیے ’الشریعہ‘ کے صفحات حاضر ہیں۔ ابو عمار زاہد الراشدی)
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد!
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اقوام سے واسطہ پڑا۔ مشرکین عرب، یہودی کینہ پرور، دیہاتی، ایسے لوگ جن کی فطرت اور خمیر میں فساد تھا، ان کے رگ وریشہ میں شر کا غلبہ تھا اور خیر کا پہلوناپید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے حسب وعدہ ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ بیماری میں مبتلا ہوئے جیسے ابو لہب، یا میدان جنگ میں مارے گئے جیسے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ، عقبہ بن ابی معیط وغیرہم۔ چند اپنی زندگی میں ناکامی، رسوائی اور مایوسی کے عالم میں طبعی موت مر گئے، جیسے رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی اور اس کا گروہ۔ یہود مدنی زندگی میں اسلام اور مسلمانوں کی روز افزوں ترقی دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ کرام کے درپے ایذا تھے۔ اس کے لیے باقاعدہ خفیہ محافل قائم کرتے اور باندیوں کو حکم دیتے کہ آپ کی ہجو میں گانے گائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار میں کمی آئے تو باذن خداوندی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے ہاتھوں خفیہ طریقوں سے ان کا کام تمام کر دیا، جیسے کعب بن اشرف اور ابو رافع جن کا قصہ احادیث میں تفصیل سے مذکور ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ان یہودی امرا کو ان کے بلند وبالا محفوظ قلعہ جات میں جا کر قتل کیا۔ اسی موقع کے لیے مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہا:
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی
مگر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا
نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا
بعض لوگ خاندانی روایات کے مطابق کبر ونخوت اور انانیت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے ہاں ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ انھوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا۔ خدا ورسول کے غیض وغضب کا نشانہ بن گئے اور قتل کیے گئے، جیسے ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا تھا کہ قتل کر دیا گیا۔
اس کے برعکس خدا تعالیٰ کے ہاں جن کی جان بخشی مقدر تھی، رحمت خداوندی نے ان کی یاوری کی، جیسے ابو سفیان اور ان کے رفقا اور وحشی بن حرب۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں جنگ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے سے روک دیا:
لَیْْسَ لَکَ مِنَ الأَمْرِ شَیْْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْْہِمْ أَوْ یُعَذَّبَہُمْ فَإِنَّہُمْ ظَالِمُونَ (آل عمران ۱۲۸)
’’تیرا اختیار کچھ نہیں۔ یا ان پر رجوع کرے یا ان کو عذاب دے کہ وہ ناحق پر ہیں۔‘‘
اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں:
’’احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر شہداء کا مثلہ کیا (ناک کان وغیرہ کاٹے)، پیٹ چاک کیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں چشم زخم پہنچا۔ سامنے کے چار دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہوا، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں، پیشانی زخمی ہوئی اور بدن مبارک لہولہان تھا۔ اسی حالت میں آپ کا پاؤں لڑکھڑایا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کفار نے مشہور کر دیا: ان محمدا قد قتل (محمد مارے گئے)۔ اس سے مجمع بد حواس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ اس وقت زبان مبارک سے نکلا کہ ’’وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا جو ان کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔‘‘ مشرکین کے وحشیانہ شدائد ومظالم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا اور ان میں سے چند نامور اشخاص کے حق میں آپ نے بددعا کا ارادہ کیا یا شروع کر دی جس میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح حق بجانب تھے، مگر حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ اپنے منصب جلیل کے موافق اس سے بھی بلند مقام پرکھڑے ہوں۔ وہ ظلم کرتے جائیں، آپ خاموش رہیں۔ جتنی بات کا آپ کو حکم ہے (مثلاً دعوت وتبلیغ اور جہاد وغیرہ)، اسے انجام دیتے رہیں۔ باقی ان کا انجام خدا کے حوالے کریں۔ اس کی جو حکمت ہوگی، وہ کرے گا۔ آپ کی بددعا سے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ کیا اس کی جگہ یہ بہتر نہیں کہ ان ہی دشمنوں کو اسلام کا محافظ اور آپ کا جاں نثار عاشق بنا دیا جائے؟ چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ بد دعا کرتے تھے، چند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کا جاں باز سپاہی بنا دیا۔ غرض لَیْْسَ لَکَ مِنَ الأَمْرِ شَیْْء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا کہ بندہ کو اختیار نہیں، نہ اس کا علم محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، سو کرے۔ اگرچہ کافر تمھارے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں، لیکن چاہے وہ ان کو ہدایت دے، چاہے عذاب کرے۔ تم اپنی طرف سے بددعا نہ کرو۔‘‘
اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹڑ دشمن، آپ اور آپ کے صحابہ کے خلاف سازشیں کرنے والے یہودی اور منافق جن کے ہاتھوں آپ بے حد تکالیف اٹھا چکے تھے، انھیں کہا گیا کہ اب بھی دروازے کھلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ بھی ان کے حق میں دعا کریں تو ان کے سب گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کو بار بار معافی دینے والا مہربان پائیں گے:
وَلَوْ أَنَّہُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَہُمْ جَآؤُوْکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰہَ وَاسْتَغْفَرَ لَہُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰہَ تَوَّاباً رَّحِیْماً (النساء ۶۴)
’’اور اگر وہ لوگ جس وقت انھوں نے اپنا برا کیا تھا، آتے تیرے پاس، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو البتہ اللہ کو پاتے مہربان معاف کرنے والا۔‘‘
یا رب تو کریمی ورسول تو کریم
صد شکر کہ ہستیم میان دو کریم
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو ابوسفیان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت عباس سے کہا، بچاؤ کی کیا تدبیر ہے؟ انھوں نے کہا، میرے پیچھے سواری پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے پہچان لیا۔ تلوار لے کر پیچھا کیا۔ حضرت عباس جلدی سے آنحضرت کی اقامت گاہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا:
یا رسول اللہ صلی اللہ علیک ان اللہ امکنک من عدوک من غیر عقد ولا صلح ودعنی ان اقتلہ، قال عباس: مہلا فانی اجرتہ
’’یا رسول اللہ، اللہ نے بغیر عقد وصلح کے آپ کے دشمن پر قدرت دی ہے۔ مجھے اس کو قتل کرنے دیں۔ حضرت عباس نے کہا، چھوڑ دو۔ میں نے اسے پناہ دی ہے۔‘‘
حضرت عباس کی فہمائش پر ابو سفیان ایمان لائے۔ آنحضرت نے فرمایا: من دخل دار ابی سفیان فھو آمن۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، وہ امن والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا: یا رسول اللہ، میرے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں! اس پر آپ نے فرمایا:
من اغلق الباب علی نفسہ فہو آمن، ومن القی السلاح فہو آمن، ومن تعلق باستار الکعبۃ فہو آمن الا ابن خطل ویعیش بن صبابۃ وقینتین لابن خطل کانتا تغنیان بھجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی باب الکعبۃ وفیہا رؤساء قریش، فاخذ بعضادتی الباب وقال: ماذا ترون ان صانع بکم؟ فقالوا اخ کریم وابن اخ کریم ملکت فاسجح، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: انی اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوتہ: لا تثریب علیکم الیوم، یغفر اللہ لکم، وہو ارحم الراحمین، انتم الطلقاء لکم اموالکم (المبسوط لشمس الائمۃ السرخسی، ج ۱۰ ص ۳۹، ۴۰ طبع دار المعرفۃ بیروت لبنان)
’’جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، وہ امن والا ہے۔ جو ہتھیار پھینک دے، وہ امن والا ہے۔ جو کعبے کے پردوں سے لپٹ جائے، وہ امن والا ہے، سوائے ابن خطل اور یعیش بن صبابہ اور ابن خطل کی دو لونڈیوں کے جو آپ کی ہجو میں گانا گایا کرتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے سامنے تشریف لائے۔ اس میں قریش کے امرا موجود تھے۔ آپ نے بیت اللہ کی دونوں چوکھٹیں پکڑ کر کہا، تمھارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انھوں نے کہا، ہمارے مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہو۔ تیرا اختیار ہے، پس برتاؤ میں نرمی اختیار کر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم سے وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی۔ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اللہ تمھیں بخش دے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم آزاد ہو۔ تمہارے مال تمہارے ہی ہیں۔‘‘
کعب بن زہیر نامی شخص اہل نجد سے، خاندانی شاعر تھا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی اور مسلمانوں کی عورتوں سے اپنا معاشقہ جتلاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ وہ روپوش ہو گیا۔ اسی حال میں مدینہ حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا: کعب بن زہیر کے لیے معافی ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو کہا: میں کعب بن زہیر ہوں۔ اسلام قبول کیا۔ وقتی طور پر آپ کو غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا: وقد قلت کذا وکذا؟ تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟ اس نے اسی مجلس میں آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مدح میں ایک طویل قصیدہ پڑھا جس میں ہے:
انبئت ان رسول اللہ اوعدنی
والعفو عند رسول اللہ مامول
لا تاخذنی بقول الوشاۃ ولم
اذنب وان کثرت فی الاقاویل
ان الرسول لنور یستضاء بہ
وصارم من سیوف اللہ مسلول
’’مجھے بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ نے مجھے دھمکی دی ہے۔ رسول اللہ کے ہاں معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ چغل خور لوگوں کی باتوں پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگرچہ میرے بارے میں بہت باتیں کہی گئیں۔ (ع یقین کس کس کا تم کرو گے، ہزار منہ ہیں ہزار باتیں)۔ اللہ کے رسول ایسا نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک قاطع تلوار ہیں۔‘‘
امام سبکی الشافعیؒ نے السیف المسلول میں ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبار بن اسود بن عبد المطلب کے قتل کا حکم دیا۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ میں آپ کو ایذا اور گالی دینے پر حریص تھا۔ میں شرم سار ہوں، مجھ سے درگزر فرمائیے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اس کی معذرت کے باعث سر جھکا لیا اور آپ فرما رہے تھے: قد عفوت عنک والاسلام یجب ما کان قبلہ۔ میں نے تمھیں معاف کیا اور اسلام پہلی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ (تنبیہ الولاۃ، مجموعہ رسائل ابن عابدین ص ۳۴۶)
فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار آدمیوں کے قتل کا حکم دیا۔ ان میں ایک ابن ابی سرح تھا جو کاتب وحی تھا۔ پھر مرتد ہو کر مشرک ہو گیا اور قریش مکہ سے جا ملا۔ کہا کہ میں محمد کو جیسے چاہوں، پھیر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں: عزیز حکیم یا علیم حکیم تو وہ کہتا ہے، نعم، کل صواب۔ ہر لفظ صحیح ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رضاعی بھائی تھا۔ وہ اسے بطور سفارش آپ کے سامنے لائے اور کہا یا رسول اللہ، عبد اللہ کو بیعت کر لیں۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد اس کی طرف سر اٹھایا، ہر دفعہ انکار کیا۔ حضرت عثمان کی وجاہت وعظمت کے پیش نظر اوران کے اصرار اور سفارش پر تین مرتبہ انکار کے بعد آپ نے اسے بیعت کر لیا۔ آ پ اپنے اصحاب پرمتوجہ ہوئے اور کہا کہ تم میں کوئی ایسا سمجھ دار اور ہوشیار شخص نہ تھا کہ جب میں نے اپنا ہاتھ بیعت سے روک لیا تو وہ اسے قتل کر دیتا؟ عباد بن بشیرؓ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اشارے سے بتلا دیتے۔ فرمایا، پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ اس کی آنکھوں میں خیانت ہو۔ (سنن ابی داود ج ۲ ص ۹)
یہ واقعہ قطعی دلیل ہے کہ سب وشتم کرنے والے کو توبہ کے بعد قتل نہیں کیا جا سکتا۔
ان چار میں سے دوسرے عکرمہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے۔ ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو کر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے مرحبا بالراکب کہہ کر استقبال کیا۔
القصہ انھی لوگوں میں سے بعض نے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی، کہیں معافی مانگنے والے کی عاجزی اور الحاح وزاری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤف ورحیم ذات کو معاف کرنے پر مجبور کر دیا، کچھ لوگ سفارش لائے اور دیگر لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن کا پیغام ملا۔ ان لوگوں نے صدق دل سے اسلام قبول کر لیا اور قتل ہونے سے بچ گئے۔
ائمہ احناف اور جمہور علما کا موقف
جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا آپ کو گالی دے، اسے قتل کیا جائے۔ یہ مذہب امام مالک، امام لیث، امام احمد اور امام اسحاق کا ہے اور یہی مذہب امام شافعی کا ہے۔ تاہم ہمارے متقدمین ائمہ احناف نے ردۃ کے باب میں اپنی عام کتب میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور پھر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قتل کی سزا معاف کرنے کے حق میں قبول کی جائے گی۔
قال ابو یوسف ایما رجل سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی وبانت منہ امراتہ فان تاب والا قتل وکذالک المراۃ الا ان ابا حنیفۃ قال لا تقتل المراۃ وتجبر علی الاسلام (تنبیہ الولاۃ، مجموعہ رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۳۲۴، مکتبہ عثمانیہ کوئٹہ)
’’امام ابو یوسف فرماتے ہیں: جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے یا تکذیب کرے یا آپ پر عیب لگائے یا تنقیص کرے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ اس کی عورت بھی اس سے جدا ہو گئی۔ اگر توبہ کرے تو فبہا، ورنہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا حکم ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔‘‘
الحاصل دین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر سب وشتم کرنے والے غیر مسلم ذمی کو سزا دی جائے اور اگر علانیہ سب وشتم سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کرے تو قتل کیا جائے۔ اسی طرح مرتد کی سزا، جبکہ وہ عاقل بالغ ہو، بالاجماع قتل ہے اور اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ مرتد کو اسلام پر مجبور کیا جائے، اگر انکار کرے تو اس کی حد قتل ہے۔ نہ اسے امن دیا جائے گا، نہ اسے غلام بنایا جائے گا اور نہ ہی اس پر جزیہ عائد کیا جائے گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ قتل کی علت محض کفر نہیں، بلکہ بالخصوص ردۃ ہی اس کی علت ہے۔ قتل ایک عقوبت خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص حق کے لیے واجب ہے اور بالخصوص ردۃ پر واجب ہوتی ہے، جس طرح شادی شدہ کے زنا پر رجم ہے۔ مرتد کا قتل کیا جانا حد ہے۔ حد لغت میں منع کو کہتے ہیں، جیسے چوکی دار کو حداد کہتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں داخل ہونے سے مانع ہے۔ جیل کے داروغہ کو سجان کہتے ہیں، کیونکہ وہ جیل سے باہر جانے سے مانع ہے۔ عقوبات خاصہ کو حدود کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ حدود معاصی کے دوبارہ ارتکاب سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ حد ثابت ہو جانے کے بعد ساقط نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں سفارش چل سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو زجر فرمایا جب انھوں نے مخزومیہ عورت کی، جس نے چوری کی تھی، سفارش کی۔ فرمایا: اتشفع فی حد من حدود اللہ؟ کیا تو اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں سفار ش کرتا ہے؟ فی الحقیقت حدود، ارتکاب معاصی سے پہلے مانع اور ارتکاب کے بعد زاجر ہیں یعنی معاصی کی طرف لوٹنے سے باز رکھتی ہیں۔ (تنبیہ الولاۃ مع الاختصار ص ۳۱۸)
توہین رسالت کی سزا فقہ حنفی کی روشنی میں
محمد مشتاق احمد
الحمد للہ ، و الصلاۃ و السلام علی رسول اللہ ، و علی آلہ و اصحابہ و من والاہ ۔
زیر نظر مسئلے پر بحث کے دوران یہ بات مسلسل مد نظر رہے کہ کسی شخص کو باقاعدہ عدالتی کاروائی کے بغیر محض سنی سنائی بات پر یا محض الزام کی بنیاد پر ’’گستاخ رسول ‘‘ نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ (۱) پس پہلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو عدالت میں گستاخ رسول ثابت کرنے کے لیے ضابطہ اور معیار ثبوت کیا ہے ؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ متعین کیا جائے کہ توہین رسالت کے جرم کی نوعیت کیا ہے کیونکہ جرم کی نوعیت کے مختلف ہونے سے اس کے اثبات کا طریقہ بھی مختلف ہوجاتا ہے ؟ (۲)
’’توہین رسالت ‘‘کے جرم کی دو مختلف صورتیں
فقہاے احناف کا موقف یہ ہے کہ ملزم کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے سے اس جرم کی نوعیت پر فرق پڑتا ہے ۔ اگر کسی مسلمان نے اس شنیع جرم کا ارتکاب کیا تو وہ مرتد ہوجاتاہے اور اس فعل پر ان تمام احکام کا اطلاق ہوگا جو ارتداد کی صورت میں لاگو ہوتے ہیں ، جبکہ غیر مسلم چونکہ مرتد نہیں ہوسکتا اس لیے اگر غیر مسلم اس فعل کاارتکاب کرے تو اس کے اثرات بھی مختلف ہوں گے ۔ (۳)
ارتداد کے قانونی اثرات
پہلے اس شخص کا معاملہ لیجیے جو پہلے مسلمان تھا لیکن توہین رسالت کے نتیجے میں مرتد ہوگیا ۔
۱ ۔ ارتداد کے احکام میں ایک اہم حکم یہ ہے کہ ارتداد کی سزا چونکہ حد ہے (۴) اس لیے اس کے اثبات کے لیے ایک مخصوص ضابطہ ہے ، جو آگے ذکر کیا جائے گا ۔ اس مخصوص ضابطے کے سوا کسی اور طریقے سے اس جرم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
۲ ۔ حد کی سزا شبھۃ سے ساقط ہوتی ہے ۔ (۵) اب چونکہ حد ارتداد تکفیر کے بعد ہی نافذ کی جاسکتی ہے اس لیے کسی بھی ایسے قول یا فعل کی بنیاد پر یہ سزا نہیں دی جاسکتی جس کے کفر ہونے یا نہ ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہو ۔ (۶) اسی طرح اگر کسی قول یا فعل کی ایک سے زائد تعبیرات ممکن ہوں اور ان میں کوئی تعبیر ایسی ہو جس کی رو سے اسے کفر نہ قرار دیا جاسکتا ہو تو اسی تعبیر کو اپنایا جائے گا ۔ (۷) چنانچہ ملزم سے پوچھا جائے گا کہ اس قول یا فعل سے اس کی مراد کیا تھی، الا یہ کہ وہ کفر بواح کا مرتکب ہوا ہو ۔ (۸) اگر ملزم کفر سے انکاری ہو تو اس کے انکار کو قبول کیا جائے گا خواہ اس کے خلاف گواہ موجود ہوں کیونکہ اس کے اس انکار کو رجوع اور توبہ سمجھا جائے گا ۔ (۹)
۳ ۔ اگر اقرار یا گواہی کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ ملزم کا متعلقہ قول یا فعل ارتداد کے زمرے میں آتا ہے تو عدالت اسے توبہ کے لیے تلقین کرے گی اور سوچ بچار کے لیے تین دن کی مہلت دے گی ۔ (۱۰) اگر وہ اس کے بعد بھی اپنے اس قول یا فعل سے رجوع کرکے اس سے مکمل براء ت کا اظہار نہ کرے تب عدالت اسے سزا سنائے گی اور یہ سزا ناقابل معافی ہوگی ۔ (۱۱) پوری امت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس سزا کو نافذ کرے۔ (۱۲)
۴ ۔ چونکہ ارتداد کی سزا حد ہے اس لیے اس کا نفاذ افراد کاکام نہیں ، بلکہ حکومت کا کام ہے ۔ اس کی مزید وضاحت آگے آرہی ہے ۔
۵ ۔ کسی شخص کے مرتد ثابت ہوجانے کے بعد اس کی عائلی زندگی پر بھی دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔ مثلاً اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہوجاتی ہے (۱۳) اور ارتداد کے بعد وہ جس مال کا مالک بنا ہو وہ اس کی موت کے بعد اس کے ورثا کو نہیں ملے گا ۔ (۱۴)
اگر ذمی توہین رسالت کا ارتکاب کرے
اگر ملزم غیر مسلم ہو تو اس فعل کو کفر میں اضافہ کہا جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ارتداد نہیں کہا جاسکتا ۔ (۱۵) چنانچہ فقہا اس مسئلے کو ارتداد کے بجائے نقض ذمہ کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں اور یہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذمی کے اس فعل سے اس کا عقد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔
فقہاے احناف کا مسلک یہ ہے کہ ذمی کے اس فعل سے اس کا عقد ذمہ نہیں ٹوٹتا ۔ (۱۶) تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فعل شنیع کے ارتکاب پر ذمی کو سزا نہیں دی جاسکے گی ۔ بہ الفاظ دیگر ان کا موقف یہ ہے کہ اس فعل سے ذمی کادار الاسلام میں سکونت کا حق ختم نہیں ہوجاتا لیکن چونکہ یہ فعل دار الاسلام کے ملکی قانون کے تحت جرم ہے اس لیے اسے سزا دی جاسکے گی ۔ اس قسم کی سزا کو فقہاے احناف سیاسۃ کہتے ہیں۔ (۱۷)
حد اور سیاسۃ میں فرق
حد اور سیاسۃ میں کئی فروق ہیں ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چند اہم فروق واضح کیے جائیں ۔
اسلامی قانون کی اصطلاح میں حد کی سزا کا تعلق حق اللہ سے ہے۔ (۱۸) حق اللہ قرار دینے کے کئی اہم نتائج ہیں :
۱ ۔ حد کی سزا قیاس و رائے سے نہیں بلکہ نص کے ذریعے مقرر کی گئی ہے جس میں کمی و بیشی کا اختیار ریاست کے پاس نہیں ہے ۔ (۱۹)
۲ ۔ حد کی سزا شبھۃ سے ساقط ہوجاتی ہے اور شبھۃ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جرم کے ثبوت کے متعلق جج کے ذہن میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے جس کا فائدہ (Benefit of the Doubt ) وہ ملزم کو دے دیتا ہے ، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر ملزم کے ذہن میں اس فعل کے قانونی جواز کے متعلق کوئی ابہام ، حقیقۃً یا فرضاً ، پایا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے اسے حد کی سزا نہیں دی جاسکے گی ۔ (۲۰)
۳ ۔ حد کی سزا کے اثبات کے لیے صرف دو ہی طریقے ہیں ، کسی تیسرے طریقے سے اس جرم کو ثابت نہیں کیا جاسکتا : ایک مجرم کی جانب سے عدالت کے سامنے آزادانہ اقرار جرم اور دوسرا اس کے خلاف گواہی جو ایک مخصوص نصاب کے مطابق ہو ۔ (۲۱) وہ مخصوص نصاب یہ ہے کہ حد زنا کے ماسوا تمام حدود میں کم سے کم دو ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد گواہی دیں جن کا کردار بے داغ ہو ۔ (۲۲) حد زنا کے اثبات کے لیے باقی شروط تو یہی ہیں لیکن گواہوں کی تعداد چار ہونی چاہیے ۔ (۲۳)
۴ ۔ حد کی سزا کی معافی کا اختیار نہ متاثرہ فرد کے پاس ہے اور نہ ہی حکومت یا ریاست کے پاس ۔ (۲۴)
سیاسۃ کی سزا کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں حق الامام کہتے ہیں ۔ (۲۵) حق الامام قرار دینے کے اہم نتائج یہ ہیں :
۱ ۔ اس سزا کی کوئی کم یا زیادہ حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے بلکہ اس کی حد مقرر کرنے کا اختیار حکومت کو دیاہے اور حکومت اس کی بعض شنیع صورتوں میں سزاے موت بھی مقرر کرسکتی ہے ۔ (۲۶)
۲ ۔ یہ سزا فعل کے قانونی جواز کے متعلق ملزم کے ذہن میں پائے جانے والے ابہام کی بنا پر ساقط نہیں ہوسکتی ۔ (۲۷)
۳ ۔ اس جرم کے اثبات کے لیے کوئی مخصوص ضابطہ نہیں ہے بلکہ جس طرح کا ثبوت عدالت کو فعل کے وقوع کے بارے میں مطمئن کردے وہ قابل قبول ہے اور اس کی بنا پر مناسب سزا دی جاسکتی ہے ۔ (۲۸)
۴ ۔ اس سزا کی معافی کا اختیار حکومت کے پاس ہے ۔ (۲۹)
اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ایک صورت میں حد ہے اگر فعل کا مرتکب اس فعل کے ارتکاب سے پہلے مسلمان ہو ، اور دوسری صورت میں سیاسۃ اگر اس فعل کا مرتکب پہلے ہی سے غیر مسلم ہو ۔
اب آئیے توہین رسالت کے جرم کی ہر دو صورتوں کی سزا کے نفاذ کی طرف ۔
حدود کا نفاذ حکمران کا حق ہے
فقہا نے تصریح کی ہے کہ حدود کا استیفاء حکمران کا حق ہے ۔ اس لیے اصولی طور پر حدود کا نفاذ حکمران کے ماسوا کوئی اور شخص نہیں کرسکتا۔ (۳۰)
اسی اصول پر طے کیا گیا ہے کہ اگر ملک کا سب سے برتر حکمران حد کے جرم کا ارتکاب کرے تو اسے حد کی سزا نہیں دی جاسکے گی کیونکہ وہ خود اپنے اوپر حد کا نفاذ نہیں کرسکتا اور کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حد نافذ کرے ۔ (۳۱)
تاہم اگر عدالت میں ثابت ہوجائے کہ کسی شخص نے حد کے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے بعد کوئی اور شخص اپنی جانب سے اس مجرم پر سزا کا نفاذ کرے تو اس صورت کو فقہا افتیات کے عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں ۔ افتیات سے مراد یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی جانب سے حد کا نفاذ کرکے حکمران کا حق ضائع کردیا ہے اور اس طرح فساد کا مرتکب ہوا ہے۔ (۳۲)
اس کی تعبیر کے لیے آج کل ہم ’’ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ‘‘ کی ترکیب استعمال کرتے ہیں ۔
قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر حد کی سزا کا نفاذ
اگر کسی شخص نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر حد کے مجرم کو سزا دی تو فقہا یہاں دو صورتیں ذکر کرتے ہیں :
ایک یہ کہ اس نے حد کے بجائے کچھ اور سزا دی تو ظاہر ہے کہ وہ فساد کا مرتکب ہوا اور اس لیے مناسب سزا کا مستحق بھی ہے ؛ (۳۳)
دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے حد کی مقررہ سزا ہی دی اور سزا کے نفاذ کی شروط کا لحاظ رکھا ، تب بھی افتیات کے مرتکب اس شخص کو حق الامام کی پامالی ، یا بہ الفاظ دیگر فساد کے ارتکاب ، پر حکمران مناسب سزا دے سکتا ہے ۔ (۳۴)
یہ سزا چونکہ حق الامام میں دی جائے گی اس لیے اس پر ان تمام احکام کا اطلاق ہوگا جو سیاسۃً دی جانے والی سزا کے لیے ہیں۔(۳۵)
واضح رہے کہ یہ حکم وہاں ہے جہاں پہلے سے ہی ثابت ہو کہ قانون ہاتھ میں لے کر جس شخص کو سزا دی گئی اس نے حد کے جرم کا ارتکاب کیا تھا ۔ اگر پہلے یا بعد میں اس کا جرم ثابت نہیں کیا جاسکا تو پھر قانون ہاتھ میں لینے والا یہ شخص اس عدوان کے لیے الگ سزا کا مستحق ہوگا جو اس نے اس شخص پر کیا تھا ۔ (۳۶)
گستاخ رسول کے معاملے میں چونکہ حد ارتداد کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے مقررہ حد سزاے موت ہے ۔ پس اگر افتیات کے مرتکب شخص نے کسی شخص کو گستاخ رسول سمجھ کر قتل کردیا اور اس نے عدالت میں مقررہ ضابطے پر ثابت کردیا کہ مقتول واقعی گستاخ رسول تھا ، تو اس صورت میں اسے قصاصاً سزاے موت نہیں دی جاسکے گی کیونکہ مقتول مرتد ہونے کی وجہ سے مباح الدم تھا ۔ البتہ افتیات کے ارتکاب کی وجہ سے قاتل کو مناسب تادیبی سزا دی جاسکے گی ۔
اگر مقتول کو مقررہ ضابطے پر گستاخ رسول اور مرتد ثابت نہ کیا جاسکا تو قاتل کو مومن کے قتل عمد کا ذمہ دار ٹھہرا کر قصاصاً سزاے موت دی جائے گی ۔ نیز اسے فساد کے ارتکاب کی وجہ سے سیاسۃً کوئی اور مناسب سزا بھی دی جاسکے گی ۔
سیاسۃ کا نفاذ بھی حکمران کا حق ہے
سیاسۃ کی سزا چونکہ حق الامام میں دی جاتی ہے اس لیے اس کا استیفاء بھی حکمران ہی کا حق ہے ۔ (۳۷)
جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ، اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والا پہلے ہی سے غیر مسلم تھا تو اسے دی جانے والی سزا حد ارتداد نہیں ، بلکہ سیاسۃ ہے ۔ یہ بھی مذکور ہوا کہ سیاسۃً دی جانے والی سزا کی کوئی مقررہ حد نہیں ہے بلکہ اسے حکمران اور عدالت کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے ، اس لیے ضروری نہیں کہ اس غیر مسلم کو سزاے موت ہی دی جائے ۔ باقی اصول وہی ہیں جو اوپر حد کے سلسلے میں ذکر ہوئے ۔
چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی غیر مسلم کو گستاخ رسول قرار دیتے ہوئے قتل کردیا تو دیکھا جائے گا :
اگر مقتول کا جرم ثابت تھا اور اسے سزاے موت سنائی گئی تھی تو اس کے قاتل سے قصاص نہیں لیا جاسکے گا لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر اسے مناسب تادیبی سزا دی جاسکے گی ۔
اگر مقتول کا گستاخ رسول ہونا ثابت نہیں کیا جاسکا ، یا اسے سزاے موت کے بجائے کوئی اور سزا دی گئی تھی ، یا اس کی سزا میں تخفیف یا معافی کی گئی تھی ، اور اس کے باوجود اسے قتل کردیا گیا ، تو ان تمام صورتوں میں چونکہ وہ مباح الدم نہیں تھا اس لیے اس کے قاتل سے قصاص لیا جائے گا اور اسے سیاسۃً مزید سزا بھی دی جاسکے گی ۔
خلاصۂ بحث
آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مباحث کا خلاصہ چند نکات کی صورت میں پیش کیا جائے :
۱ ۔ کسی شخص کو اس وقت تک ’’گستاخ رسول ‘‘ قرار نہیں دیا جاسکتا جب تک مقررہ شرعی ضابطے پر اس کا جرم ثابت نہ ہو ۔
۲ ۔ اگر گستاخ رسول اس جرم سے پہلے مسلمان تھا تو اس کے اس جرم پر ارتداد کے احکام کا اطلاق ہوگا اور اگر وہ پہلے ہی غیر مسلم تھا تو پھر اس فعل پر سیاسۃ کے احکام کا اطلاق ہوگا ۔
۳ ۔ حد ارتداد کو ملزم کے اقرار یا دو ایسے مسلمان مردوں کی گواہی ، جن کا کردار بے داغ ہو ، سے ہی ثابت کیا جاسکتا ہے ، جبکہ سیاسۃ کو عورتوں اور غیر مسلموں کی گواہی ، نیز قرائن اور واقعاتی شہادتوں سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے ۔
۴ ۔ پہلی صورت میں سزا بطور حد موت ہے لیکن سزا کے نفاذ سے پہلے عدالت مجرم کو توبہ کے لیے کہے گی اور اگر عدالت اس کی توبہ سے مطمئن ہو تو اس کی سزا ساقط کردے گی ۔ دوسری صورت میں کوئی مقررہ سزا نہیں ہے بلکہ جرم کی شدت و شناعت اور مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت مناسب سزا سنائے گی ، جو بعض حالات میں سزاے موت بھی ہوسکتی ہے ۔ سیاسۃً دی جانے والی سزا کو حکومت معاف کرسکتی ہے اگر مجرم کا طرز عمل تخفیف کا متقاضی ہو ۔
۵ ۔ حد ارتداد حق اللہ ہے اور سیاسۃ کی سزا حق الامام ہے ، اور حنفی فقہا کے مسلمہ اصولوں کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق الامام دونوں سے متعلق سزاؤں کا نفاذ حکومت کا کام ہے ۔
۶ ۔ اگر کسی شخص نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے شخص کو قتل کیا جو پہلے مسلمان تھا لیکن توہین رسالت کے نتیجے میں مرتد ہوگیا تھا اور اس کا جرم مقررہ ضابطے پر ثابت ہوا تھا ، تو قاتل کو قصاص کی سزا نہیں دی جائے گی لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر اس قاتل کو سیاسۃً مناسب سزا دی جاسکے گی ۔ اگر مقتول کا جرم مقررہ ضابطے پر ثابت نہیں ہوا تھا تو سیاسۃ کے علاوہ قاتل کو قصاص کی سزا بھی دی جائے گی ۔
۷ ۔ اگر مقتول پہلے سے ہی غیر مسلم تھا اور اس کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا تھا ، یا اسے عدالت کی جانب سے سزاے موت نہیں سنائی گئی تھی ، یا اس سزا میں تخفیف کی گئی تھی ، تو قاتل کو قصاص کی سزا بھی دی جائے گی اور سیاسۃً کوئی اور مناسب سزا بھی سزا بھی دی جاسکے گی ۔ اگر مقتول کا جرم بھی ثابت تھا اور اسے سزاے موت بھی سنائی گئی تھی ، تو قاتل کو قصاص کی سزا نہیں دی جائے گی لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر تادیب کے لیے اسے سیاسۃً مناسب سزا دی جاسکے گی ۔
ھذا ما عندی ، و العلم عند اللہ ۔ اللھم أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعہ ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابہ ۔
حواشی
۱ ۔ یہ اسلامی قانون کا مسلمہ ضابطہ ہے کہ جب تک باقاعدہ عدالتی کاروائی کے نتیجے میں کسی شخص کے خلاف دعوی ثابت نہ ہوجائے اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا کیونکہ الأصل براء ۃ الذمۃ ۔ ( شہاب الدین السید أحمد بن محمد الحموی ، غمز عیون البصائر شرح کتاب الأشباہ و النظائر ( بیروت ۔ دار الکتب العلمیۃ ، ۱۹۸۵ م ) ۔ ج ۱ ، ص ۲۰۳ ۔ در اصل یہ قاعدہ ایک اور بنیادی قاعدے الیقین لا یزول بالشک کا لازمی نتیجہ ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : مصدر سابق ۔ ص ۱۹۳ ۔ ۲۴۵ ۔
۲ ۔ جیسا کہ آگے ہم واضح کریں گے ، اسلامی قانون کی رو سے حدود ، قصاص ، تعزیر اور سیاسۃ میں سے ہر ایک کے اثبات کے لیے مختلف نصاب وضع کیا گیا ہے ۔ چنانچہ ان میں سے ہر جرم اقرار سے ثابت ہوتا ہے لیکن حد زنا میں اقرار کا طریقہ دیگر جرائم میں اقرار کے طریقے سے کسی قدر مختلف ہے ۔ پھر ان میں سے ہر جرم شہادت سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے لیکن شہادت کا نصاب مختلف جرائم کے لیے مختلف ہے ۔
۳ ۔ اس موضوع پر خاتمۃ المحققین علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی کی معرکہ آرا تحقیق کے لیے ان کا رسالہ دیکھیے : تنبیہ الولاۃ و الحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابہ الکرام علیہ و علیہم الصلاۃ و السلام ۔ انھوں نے اس رسالے میں اس مسئلے کے ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور متعدد متون ، شروح اور فتاوی کا تجزیہ کرکے یہی نتیجہ نکالا ہے۔ ( مجموعۃ رسائل ابن عابدین (دمشق : المطبعۃ الھاشمیۃ ، ۱۳۲۵ ھ ) ۔ ج ۱ ، ص ۳۱۳ ۔ ۳۷۰ ۔
۴ ۔ علامہ ابن عابدین نے ارتداد کی سزا کے حد ہونے پر بھی مدلل بحث کی ہے ۔ (مجموعۃ رسائل ابن عابدین ۔ ج ۱ ، ص۳۱۸ ۔ ۳۱۹)
۵ ۔ فقہا جب شبھۃ کے نتیجے میں حدود سزاؤں کے سقوط کی بحث کرتے ہیں تو اس سے وہ ’’شک کا فائدہ‘‘ (Benefit of the Doubt) مراد نہیں لیتے ، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس سے ان کی مراد فعل کے مرتکب کو امر قانونی یا امر واقعی کے سمجھنے میں لاحق ہونے والی خطا (Mistake of Law or of Fact ) ہوتی ہے ۔ ( تفصیل کے لیے دیکھیے : Imran Ahsan Khan Nyazee, General Principles of Criminal Law: Western and Isalmic (Islamabad: Advanced Legal Studies Institute, 1998), 142-43))
۶ ۔ علامہ علاؤ الدین محمد بن علی الحصکفی فرماتے ہیں :
لا یفتی بکفر مسلم أمکن حمل کلا مہ علی محمل حسن ، أوکان فی کفر ہ اختلا ف ، ولو روا ےۃ ضعیفۃ (رد المحتار علی الدر المختار (القاھرۃ : مصطفی البابی الحلبی ، تاریخ ندارد ) ۔ ج ۳ ، ص ۳۱۶ )
[مسلمان کے کفر کا فتوی نہیں دیا جائے گا اگر اس کے کلام کی بہتر تاویل ممکن ہو ، یا اس کے کفر میں اختلاف ہو ، خواہ اختلاف ضعیف روایت سے مروی ہو ۔ ]
علامہ خیر الدین الرملی نے وضاحت کی ہے کہ اگر کسی بات کے کفر ہونے کے متعلق ہمارے مسلک میں کوئی اختلافی روایت نہ ہو لیکن کسی دوسرے مسلک میں وہ کفر کی موجب نہ ہو تب بھی کفر کا فتوی نہیں دیا جائے گا ۔ اس کی تائید میں ابن عابدین تکفیر کے لیے اس مسلمہ شرط کا ذکر کرتے ہیں :
و یدل علی ذلک اشتراط کون ما یوجب الکفر مجمعاً علیہ ۔ ( ایضاً )
[اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی بات کے موجب کفر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر اجماع ہو۔]
۷ ۔ ملا علی القاری فرماتے ہیں :
المسئلۃ المتعلقۃ با لکفر اذا کان لھا تسع و تسعون احتمالاً للکفر ، وا حتمال واحد فی نفیہ ، فا لأولی للمفتی والقاضی أن یعمل بالاحتمال النافی ، لأن الخطاء فی ابقاء ألف کافر أھون من الخطا ء فی افناء مسلم واحد (شرح الفقہ الأکبر (کراچی : محمد سعید اینڈ سنز ، تاریخ ندارد ) ۔ ص ۱۹۵ )
[ کفر سے متعلق مسئلے میں اگر ننانوے احتمالات کفر کے ہوں اور ایک احتمال کفر کی نفی کا ہو تو مفتی اور قاضی کو چاہیے کہ کفر کی نفی کے احتمال پر عمل کرے کیونکہ ایک ہزار کافروں کے باقی چھوڑنے کی غلطی ایک مسلمان کے قتل کرنے کی غلطی کی بہ نسبت ہلکی غلطی ہے ۔ ]
۸ ۔ چنانچہ جن نصوص میں قرار دیا گیا ہے کہ کفر کی موجب کوئی بات کہنے والے شخص یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ اسے اس بات کے کفر ہونے کا علم نہیں تھا ، بلکہ اسے تجدید ایمان کے لیے کہا جائے گا ، ان کا محل یہی ہے کہ جب بات بالکل صریح اور قطعی طور پر موجب کفر ہو ، اور اس کی بہتر تاویل ممکن نہ ہو ، تو اسے کفر ہی سمجھا جائے گا ۔ ( رد المحتار ۔ ج ۳ ، ص ۳۱۶ )
۹ ۔ کمال الدین محمد ابن الھمام الاسکندری نے صراحت کی ہے :
اذا شھدوا علی مسلم بالردۃ، وھو منکر، لا یتعرض لہ، لا لتکذیب شھود العدول، بل لأن انکارہ توبۃ ورجوع ( فتح القدیر علی الھدایۃ شرح بدایۃ المبتدی (القاھرۃ : دارالکتب العربیۃ ، ۱۹۷۰ء ) ۔ ج ۵، ص ۳۳۲ )
[اگر گواہ کسی مسلمان کے ارتداد کی گواہی دیں ، اور وہ اس سے انکاری ہو ، تو اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی ، اس لیے نہیں کہ سچے گواہوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا ، بلکہ اس لیے کہ ملزم کے انکار کو توبہ اور رجوع سمجھا جائے گا۔]
۱۰ ۔ ابن عابدین نے تفصیل سے احناف کا یہ موقف واضح کیا ہے کہ مسلمان توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اس پر ارتداد کے احکام لاگو ہوتے ہیں جن میں ایک حکم یہ ہے کہ اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا اور اگر اس نے توبہ کی تو وہ مقبول ہوگی ۔ (مجموعۃ رسائل ابن عابدین ۔ ج ۱ ، ص ۳۲۰ ۔ ۳۴۸ ) انھوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ توبہ کی قبولیت سے مراد یہ ہے کہ اسے دنیوی سزا نہیں دی جائے گی ، باقی رہی آخرت کی سزا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے ۔
معنی قبول التوبۃ عندنا سقوط القتل عنہ فی الدنیا ، و نجاتہ من العذاب فی الآخرۃ ان طابق باطنہ ظاھرہ (ایضاً۔ ص ۳۲۴)
[توبہ کی قبولیت کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس سے دنیا میں سزاے موت ساقط ہوجائے گی اور آخرت میں وہ نجات پائے گا ، اگر اس کاباطن اس کے ظاہر کے مطابق ہو ۔ ]
و أما الحکم الأخروی فانہ مبنی علی حسن العقیدۃ و صدق التوبۃ باطناً ، و ذلک مما یختص بعلمہ علام الغیوب جل و علا ۔ ( ایضاً )
[جہاں تک اخروی حکم کا تعلق ہے تو وہ باطنی طور پر صحیح عقیدے اور سچی توبہ پر منحصر ہے ، جس کا علم صرف خفیہ رازوں کے جاننے والے بزرگ و برتر ذات کے پاس ہے ۔ ]
۱۱ ۔ حق جس کا ہوتا ہے اسی کے پاس معافی کا اختیار بھی ہوتا ہے ۔ کسی کام کو حق اللہ قرار دینے کا قانونی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں معافی کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا ، حتی کہ معاشرہ یا حکمران بھی اسے معاف نہیں کرسکتا ۔ چنانچہ ملک العلماء علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی یہ ثابت کرنے کے بعد کہ قذف یا تو خالصتاً حق اللہ ہے یااس میں حق اللہ غالب ہے ، قرار دیتے ہیں :
واذا ثبت أن حد القذف حق اللہ تعالی خالصاً أو المغلب فیہ حقہ فنقول : لا یصح العفو عنہ ، لأن العفو انما یکون من صاحب الحق ، و لا یصح الصلح و الاعتیاض ، لأن الاعتیاض عن حق الغیرلا یصح ، و لا یجری فیہ الارث ، لأن الارث انما یجری فی المتروک من ملک أو حق للمورث ۔۔۔ و لم یوجد شیء من ذلک فلا یورث ، و یجری فیہ التداخل ۔ (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، تحقیق علی المعوض و عادل أحمد عبد الموجود ( بیروت : دار الکتب العلمیۃ ، ۲۰۰۳ء )۔ ج ۹ ، ص ۲۵۰ )
[اور جب یہ ثابت ہوا کہ حد قذف اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے ، یا اس میں غالب حق اللہ کا ہے تو ہم کہتے ہیں ( کہ اس کے نتائج یہ ہیں) : کہ اس کا معاف کرنا صحیح نہیں ہے ، کیونکہ معافی صاحب حق کی طرف سے ہوتی ہے ۔ اسی طرح اس میں صلح یا عوض قبول کرنا بھی صحیح نہیں ، کیونکہ کسی اور کے حق کا عوض لینا (یا کسی اور کے حق پر صلح کرنا) صحیح نہیں ۔ اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، کیونکہ وراثت تو مورث کی چھوڑی ہوئی ملکیت یا حق میں جاری ہوتی ہے ...اور اس قسم کی کوئی چیز یہاں نہیں پائی جاتی ، اس لیے اس میں وراثت نہیں ہوتی ۔ اور اس میں تداخل جاری ہوتی ہے (یعنی ایک ہی نوعیت کے کئی جرائم کے ارتکاب پر ایک ہی سزا ملتی ہے ) ۔ ]
۱۲ ۔ انگریزی قانون میں حقوق کو بنیادی طور دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے : انفرادی حق (Private Right) اور اجتماعی حق (Public Right)۔اس تقسیم سے لاشعوری طور پر متاثر ہونے کے سبب سے کئی لوگوں نے قرار دیا کہ اسلامی قانون میں حق العبد سے مراد Private Right اور حق اللہ سے مراد Public Right ہے ۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بعض اوقات فقہا حق السلطان یا حق الامام کی بھی بات کرتے ہیں تو انہوں نے قرار دیا کہ حق الامام اور حق اللہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں ۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو دیگر کئی سنگین غلطیوں کا باعث بنی ہے ۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، حق جس کا ہوتاہے، اسے جرم کی معافی کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ اگر حقوق اللہ اور حقوق الامام ایک ہی ہوتے تو پھر جن جرائم کو حقوق اللہ سے متعلق سمجھا جاتاہے (حدود) ان میں ریاست کے پاس معافی کا اختیارہوتا۔
۱۳ ۔ امام ابوحنیفہ کے ممتاز شاگرد امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے تصریح کی ہے :
و أیما رجل مسلم سبّ رسول اللہ ﷺ، أو کذّبہ، أو عابہ ، أو تنقصہ ، فقد کفر باللہ تعالیٰ ، و بانت منہ امرأتہ ۔ فان تاب ، و الا قتل ۔ ( کتاب الخراج ( بیروت : دار المعرفۃ للطباعۃ و النشر ، ۱۹۷۹ م ) ۔ ص ۱۸۲ )
[جو مسلمان رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرے ، یا ان کی تکذیب کرے ، یا ان کی عیب جوئی کرے ، یا ان کی شان میں تنقیص کرے ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے کفر کا ارتکاب کیا اور اس کی بیوی بائن ہوگئی ۔ پس اگر اس نے توبہ کی تو بہتر ، ورنہ اسے سزاے موت دی جائے گی ۔ ]
۱۴ ۔ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی ، الھدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی ( بیروت : دار احیاء التراث العربی ، ۱۹۹۵ م ) ۔ ج ۱ ، ص ۴۰۷ ۔
۱۵ ۔ امام کاسانی فرماتے ہیں :
لو سبّ النبی ﷺ لا ینتقض عھدہ لأن ھذا زیادۃ کفر علی کفر ، و العقد یبقی مع أصل الکفر فیبقی مع الزیادۃ ۔ ( بدائع الصنائع ۔ ج ۹ ، ص ۴۴۷ ۔ ۴۴۸)
[ اگر ذمی نے نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کی تو اس کا عقد ذمہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ کفر پر مزید کفر کا اضافہ ہے ، اور عقد جب اصل کفر کے ساتھ باقی تھا تو اضافے کے ساتھ بھی باقی رہے گا ۔ ]
۱۶ ۔ صاحب ہدایۃ کے الفاظ قابل غور ہیں ۔
ان سبّ النبی ﷺ کفر ، و الکفر المقارن لا یمنعہ ، فالطارئ لا یرفعہ ( الھدایۃ ۔ ج ۱ ، ص ۴۰۵ )
[رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کفر ہے ، اور جب عقدذمہ کے وقت موجود کفر اس عقد کے انعقاد سے مانع نہیں تھا تو عقد کے بعد طاری ہونے والا کفر اس عقد کو ختم بھی نہیں کرسکتا۔]
علامہ ابن الہمام نے حنفی مذہب کے اس موقف سے مختلف رائے اپنائی ہے ۔ وہ کہتے ہیں :
و الذی عندی أن سبّہ ﷺ أو نسبۃ ما لا ینبغی الی اللہ تعالیٰ ان کان مما لا یعتقدونہ کنسبۃ الولد الی اللہ تعالیٰ و تقدس عن ذلک اذا أظھرہ یقتل بہ ، و ینتقض عھدہ وان لم یظھر ولکن عثر علیہ وھو یکتمہ فلا ( فتح القدیر ۔ ج ۵ ، ص ۳۰۳)
[میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ علانیہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی یا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو ان اعتقاد کا حصہ نہ ہو ، جیسے اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت حالانکہ اس کی شان اس سے اونچی اور پاک ہے ، تو اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے اس کا عہد ٹوٹ جائے گا ۔ اور اگر وہ اس کا اظہار نہ کرے بلکہ اسے ایسی حالت میں پکڑا گیا جب کہ وہ چوری چھپے یہ کررہا تھا تو نہیں ۔ ]
اس پر نقد کرتے ہوئے خیر الدین الرملی کہتے ہیں :
ان ما بحثہ فی النقض مسلّم مخالفتہ للمذھب ، و أما ما بحثہ فی القتل فلا ۔ ( علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی، رد المحتار علی الدر المختار (القاھرۃ : مصطفی البابی الحلبی ، تاریخ ندارد ) ۔ ج ۳ ، ص ۳۰۵ )
[جو تحقیق اس نے عہد ٹوٹ جانے کے متعلق کی ہے اس کا مذہب حنفی کے خلاف ہونا مسلم ہے ، البتہ جو تحقیق اس نے سزاے موت کے متعلق کی ہے وہ مذہب حنفی کے خلاف نہیں ہے۔]
ابن عابدین نے ابن الہمام کے دفاع میں اس قول کی تاویل اس طرح کی ہے کہ اظھار سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے عادت بنالے یا کھلے عام گستاخی کا ارتکاب کرکے متمرد اور مفسد بن جائے ۔ ( ایضاً ، ص ۳۰۶ ) تاہم اس تاویل کے باوجود ابن الہمام کا قول حنفی مذہب کے مطابق نہیں ہے کیونکہ بات اگر صرف قتل کے جواز تک ہوتی تو ٹھیک تھی لیکن وہ عقد ذمہ ٹوٹ جانے کے بھی قائل ہیں ۔ اسی وجہ سے الخیر الرملی کی بات صحیح ہے کہ عقد ذمہ ٹوٹنے کی بات درست نہیں ہے ، البتہ قتل کے جواز کی بات صحیح ہے ۔
۱۷ ۔ علامہ ابن عابدین شامی سیاسۃ اور تعزیر کے تصورات میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں :
قلت : و الظاھر أن السیاسۃ و التعزیر مترادفان ۔ و لذا عطفوا أحدھما علی الآخر لبیان التفسیر ، کما وقع فی الھدایۃ و الزیلعی و غیرھما ۔ بل و اقتصر فی الجوھرۃ علی تسمیتہ تعزیراً .... و قالوا ان التعزیر موکول الی رأی الامام ۔ فقد ظھر لک بھذا ان باب التعزیر ھو المتکفل لأحکام السیاسۃ ....وبہ علم أن فعل السیاسۃ یکون من القاضی أیضاً ، و التعبیر بالامام لیس للاحتراز عن القاضی ، بل لکونہ ھو الأصل و القاضی نائب عنہ فی تنفیذ الأحکام ۔ ( ایضاً )
[میری رائے یہ ہے کہ بظاہر سیاسۃ اور تعزیر مترادف ہیں ۔ اسی وجہ سے بیان تفسیر کے طرز پر ان کو ایک دوسرے پر عطف کیا جاتا ہے ، جیسے ہدایۃ ، زیلعی اور دوسری کتابوں میں ہوا ہے ۔ بلکہ الجوھرۃ میں تو اسے صرف تعزیر کہنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے ....اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تعزیر امام کی رائے کے سپرد ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ باب تعزیر ہی سیاسۃ کے احکام پر متضمن ہے اور امام کا ذکر قاضی سے احتراز کے لئے نہیں کیا جاتا ، بلکہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ امام ہی قاضی کے اختیارات کی اصل ہے اور احکام کے نفاذ میں قاضی اس کا نائب ہے ۔ ]
ابن عابدین بہت بڑے فقیہ تھے اور انہیں بجا طور پر خاتمۃ المحققین کہا جاتا ہے مگر ہماری ناقص رائے میں سیاسۃ اور تعزیر کو مترادف قرار دینے میں ان سے تسامح ہوا ہے ۔ ان کی یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ تعزیر اور سیاسۃ کے الفاظ توسعاً ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ۔ تاہم اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مترادف ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعزیر حقوق العباد میں دی جاتی ہے اور سیاسۃ حقوق الامام میں ، اور امام چونکہ امت کا وکیل ہوتا ہے اس لیے حقوق الامام سے مراد دراصل امت کے اجتماعی حقوق ہیں ۔ پس تعزیر اور سیاسۃ دونوں در حقیقت حقوق العباد میں ہوتے ہیں ۔ اسی وجہ سے ان دونوں میں کوئی بھی سزا شبھۃ کی بنا ساقط نہیں ہوسکتی کیونکہ شبھۃ کی بنا پر صرف حقوق اللہ سے متعلق سزائیں ( حدود اور قصاص ) ساقط ہوتی ہیں۔ ان کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ قاضی کے اختیارات کے لیے اصل امام ہے اس لیے اگر سیاسۃ کو امام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ قاضی کے پاس سیاسۃ کا اختیار نہیں ہوتا ، بلکہ درحقیقت قاضی کا اختیار سیاسۃ کے قاعدے میں شامل ہوتا ہے ۔ تاہم اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دونوں مصطلحات مترادف ہیں ۔مخصوص اصطلاحی مفہوم میں ان دونوں کے درمیان کچھ اہم فروق پائے جاتے ہیں ۔
الف ۔ تعزیر چونکہ فرد کے حق سے متعلق ہوتی ہے اس لئے معافی ، صلح اور ابراء کا حق متاثرہ فرد ہی کے پاس ہوتا ہے ۔ اس کے برعکس سیاسۃ کا تعلق چونکہ امام کے حق سے ہوتا ہے اس لئے دیگر حقوق بھی امام کے پاس ہوتے ہیں ۔ شمس الائمۃ أبو بکر محمد بن أبی سہل السرخسی نے تصریح کی ہے کہ حکمران کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فرد کے حقوق کی معافی کرے ۔
لیس للامام ولایۃ اسقاط حقوق العباد ۔ ( المبسوط ، تحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعی ( بیروت : دار الکتب العلمیۃ ، ۱۹۹۷ م ) ۔ ج ۱۰ ، ص ۱۳۹ )
[امام کے پاس بندوں کے حقوق ساقط کرنے کا اختیار نہیں ہے۔]
ب ۔ تنہا عورت کی گواہی یا واقعاتی شہادتوں اور قرائن کی بنیاد پر تعزیری سزا نہیں دی جاسکتی ۔ چنانچہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ گواہوں کی تعداد کے لحاظ سے شہادت کے تین مراتب ہیں :
حد زنا کے اثبات کے لئے چار مرد گواہ چاہئیں ؛
باقی حدود اور قصاص کے اثبات کے لئے دو مرد گواہ درکا ر ہیں ؛ اور
تعزیر کے اثبات کے لئے وہی معیار ثبوت ہے جو مالی حقوق کے اثبات کے لئے ہے ، یعنی دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ۔ (المبسوط ۔ج ۱۶ ، ص ۱۳۴ ؛ الھدایۃ ۔ ج ۳ ، ص ۱۱۶۔۱۱۷ )
اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ تعزیر کا دائرۂ کار حد سے کچھ وسیع ہونے کے باوجود درحقیقت نہایت محدود ہے۔ سیاسۃ کے اثبات کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے ، بلکہ قاضی واقعاتی شہادتوں اور قرائن کی بنیاد پر بھی سزا سنا سکتا ہے ۔ مثال کے طور پر عہد رسالت میں ایک یہودی کا سر کچلنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک عورت کا سر بھاری پتھر سے کچل دیا تھا ۔ فقہاے احناف اس سزا کو سیاسۃ کہتے ہیں اور یہ سزا اقرار یا شہادت پر نہیں بلکہ قرائن اور واقعاتی شہادتوں کی بنیاد پر دی گئی تھی ۔ ( المبسوط ۔ ج ۲۶ ، ص ۱۲۶ )
ج۔ تعزیر اگر ایسے جرم میں دی جارہی ہے جس کی جنس میں حد کی سزا مشروع ہو مگر وہ شبھۃ کی بنا پر یا کسی شرط کے فقدان کی وجہ سے نہ دی جاسکتی ہو تو تعزیر کی مقدار حد سے کم ہوگی ۔ چونکہ حدود میں کم سے کم سزا غلام کے لیے شرب خمر، چالیس کوڑے، کی ہے ، اس لیے امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار انتالیس کوڑے ہے ۔ ( بدائع الصنائع ۔ ج ۹ ، ص ۲۷۱) ایسی کوئی قید اس سزا کے لئے نہیں ہے جو سیاسۃً دی جائے ۔ چنانچہ سیاسۃً سزاے موت بھی دی جاسکتی ہے ، بلکہ اس سزاے موت کے لئے کوئی عبرتناک طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے جیسا کہ اوپر یہودی کی سزا کا ذکر ہوا ۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے : محمد مشتاق احمد ، ’’ آبرو ریزی کے جرم کی شرعی تکییف ‘‘ ، معارف اسلامی ، ج ۹ ، نمبر ۱ (جنوری ۔ جون ۲۰۱۰ ء ) ۔ ص ۷۳ ۔ ۸۰۔
۱۸ ۔ امام کاسانی نے حد کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے :
عقوبۃ مقدرۃ واجبۃ حقاً للہ تعالیٰ ۔ ( ایضاً ۔ ص ۱۷۷)
[ ایسی مقررہ سزا جس کا نفاذ بطور حق اللہ واجب ہے ۔ ]
۱۹ ۔ امام سرخسی فرماتے ہیں :
الحد بالقیاس لا یثبت ۔ ( المبسوط ۔ ج ۹ ، ص ۱۱۰ )
[حد قیاس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی ۔ ]
۲۰ ۔ Nyazee, General Principles of Criminal Law, 142-43.
۲۱ ۔ امام کاسانی فرماتے ہیں :
الحدود کلھا تظھر بالبینۃ و الاقرار ، لکن عند استجماع شرائطھا ۔ ( ج ۹ ، ص ۲۲۹ )
[ تمام حدود بینہ اور اقرار سے ثابت ہوتے ہیں لیکن اسی وقت جب اس کی تمام شرائط پوری ہوں ۔ ]
آگے وہ واضح کرتے ہیں کہ بینۃ سے مراد شہادت ہے اور یہ کہ حدود میں شہادۃ علی الشہادۃ ، کتاب القاضی اور علم القاضی وغیرہ قابل قبول نہیں ہیں ۔
۲۲ ۔ نیز اگر ملزم مسلمان ہو تو گواہ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے ۔ ( بدائع الصنائع ۔ ج ۹ ، ص ۵۶ ) عورت یا غیر مسلم کی گواہی پر حد کی سزا نہیں دی جاسکتی ۔ یہ خواتین یا غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ ملزم کے ساتھ تخفیف ہے ۔
۲۳ ۔ المبسوط ۔ج ۱۶ ، ص ۱۳۴ ؛ الھدایۃ ۔ ج ۳ ، ص ۱۱۶۔۱۱۷ ۔
۲۴ ۔ اوپر ہم نے امام کاسانی کے حوالے سے حدود کی صفات ذکر کی ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ حد چونکہ حق اللہ ہے اس لیے اس میں معافی کا اختیار نہ متاثرہ فرد کے پاس ہے ، نہ ہی حکمران کے پاس ۔ (بدائع الصنائع ۔ ج ۹ ، ص۲۵۰ )
۲۵ ۔ المبسوط ۔ ج ۹ ، ص ۹۱ ۔
۲۶ ۔ چنانچہ مثال کے طور پر عادی چور ، داعی زندیق ، جادوگر ، ہم جنس پرستی کے عادی شخص اور دیگر مفسدین کی سزاے موت کو فقہاے احناف سیاسۃ ہی کہتے ہیں ۔ ( المبسوط ۔ ج ۹ ، ص ۹۰ ۔ ۹۱ ؛ الھدایۃ ۔ ج ۲، ص ۳۴۶۔۳۴۷ ؛ رد المحتار ج ۳ ، ص ۱۶۲ )
۲۷ ۔ سیاسۃ چونکہ حق اللہ نہیں ہے اور نیز تعزیر کے وسیع مفہوم میں داخل ہے ، اس لیے تعزیر کی طرح یہ بھی شبھۃ یعنی فعل کے قانونی جواز کے متعلق ملزم کے ذہن میں پائے جانے والے ابہام کی بنا پر ساقط نہیں ہوگی ۔
۲۸ ۔ چنانچہ سیاسۃ کی سزا تنہا خواتین کی گواہی ، غیر مسلموں کی گواہی ، شہادۃ علی الشہادۃ ، کتاب القاضی بلکہ واقعاتی شہادتوں اور قرائن کی بنیاد پر بھی دی جاسکتی ہے ۔
۲۹ ۔ چونکہ معافی کا اختیار صاحب حق کے پاس ہوتا ہے اور سیاسۃ کی سزا حق الامام میں دی جاتی ہے اس لیے حکمران کے پاس معافی کا اختیار ہوتا ہے ۔
۳۰ ۔ امام سرخسی نے تصریح کی ہے : استیفاء الحد الی الامام ۔ ( المبسوط ۔ ج ۹ ، ص ۱۲۱)
[حد کا استیفا امام کا کام ہے ۔ ]
۳۱ ۔ البتہ حق العبد سے تعلق رکھنے والے امور (مثلاً اموال و تعزیر ) میں حکمران پر عدالتی فیصلہ نافذ کیا جائے گا ۔ یہی حکم قصاص کا بھی ہے کیونکہ اس میں بھی حق العبد غالب ہے ۔ (المبسوط ۔ ج ۹ ، ص ۱۲۱)
۳۲ ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : افتیات کے عنوان سے مقالہ : الموسوعۃ الفقھیۃ ( الکویت : وزارۃ الأوقاف و الشؤن الاسلامیۃ ، ۱۹۸۶ء ) ۔ ج ۵ ، ص ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ ۔
۳۳ ۔ رد المحتار ۔ ج ۳ ، ص ۱۷۶ ۔
۳۴ ۔ ایضاً۔ فقہاے احناف کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی شخص کا فعل اگر فی نفسہ شرعاً جائز بھی ہو لیکن اس سے حکمران کے حق کا افتیات ہوتا ہو تو حکمران اسے مناسب تادیبی سزا سنا سکتا ہے ۔ مثال کے طور پر فقہاے احناف کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلم مقاتل کو جب قیدکیا جائے تو جیسے اسے میدان جنگ میں قتل کیا جاسکتا تھا ایسے ہی اسے قید کیے جانے کے بعد بھی قتل کیا جاسکتا ہے ( أبو بکر محمد بن أبی سہل السرخسی ، شرح کتاب السیر الکبیر ، تحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعی ( بیروت : دار الکتب العلمیۃ ، ۱۹۹۷ م ) ۔ ج ۳ ، ص ۱۲۴) کیونکہ وہ مرتد کی طرح مباح الدم ہوتا ہے ( ایضاً ۔ ص۱۲۶ ) لیکن انھوں نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ کوئی شخص اسے حکمران کی اجازت کے بغیر قتل نہیں کرے گا ۔ ( ایضاً ۔ ج ۲ ، ص ۱۹۷ ) پھر اگر کسی نے اسے حکمران کی اجازت کے بغیر قتل کیا تو اسے حکمران مناسب تادیبی سزا دے سکتا ہے کیونکہ وہ افتیات کا مرتکب ہوا ۔ (ایضاً ۔ ج ۳ ، ص ۱۲۶)
۳۵ ۔ چنانچہ مثال کے طور پر اس سزا میں کمی بیشی اور معافی کا اختیار حکمران کے پاس ہے ۔
۳۶ ۔ رد المحتار ۔ ج ۳ ، ص ۱۷۵ ۔ ظاہر ہے کہ جسے حد کی سزا دی گئی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ معصوم اور بری تھا ۔ اس لیے اس کے خلاف کیا جانے والا اقدام عدوان ہی ہے خواہ اسے حد کا نام دیا گیا ہو ۔ چنانچہ عدوان کی ماہیت کو دیکھتے ہوئے اس پر قصاص ، دیت ، ارش یا حکومۃ عدل ( جسے مجموعۂ تعزیرات پاکستان میں ’’ضمان ‘‘ کہا گیا ہے ) کے احکام کا اطلاق ہوگا ۔
۳۷ ۔ اس کی وجہ واضح ہے ۔ یہ سزا حق الامام میں دی جاتی ہے ۔ اس لیے حکمران ہی کے پاس استیفاء کا حق ہے ۔ اس کے برعکس تعزیر چونکہ حق العبد میں دی جاتی ہے اس لیے بنیادی طور پر اس میں استیفاء کا حق متاثرہ فرد یا اس کے قانونی وارث کے پاس ہوتا ہے اور حکمران کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس متاثرہ شخص کے حق کے استیفاء میں اس کی مدد کرے اور اسے اپنے حق سے تجاوز نہ کرنے دے ۔ ( بدائع الصنائع ۔ ج ۹ ، ص ۲۵۳ ) یہی حکم قصاص کا بھی ہے کیونکہ اس میں بھی حق العبد غالب ہوتا ہے ۔ ( ایضاً ۔ ج ۱۰ ، ص ۲۷۳ ۔ ۲۷۸ )
قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت (۱)
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
گزشتہ ایک ماہ کے دوران مجھے کراچی، بہاول پور، لاہور، راولپنڈی، خانیوال، کبیروالا، سرگودھا، نوشہرہ، پشاور اور دیگر شہروں میں مختلف دینی اجتماعات میں شرکت اور احباب سے ملاقاتوں کا موقع ملا اور اکثر اوقات میں دوستوں کے اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ تحریک تحفظ ناموس رسالت کی مرکزی قیادت میں اہل تشیع کی شمولیت کے بارے میں آپ کا موقف اور رائے کیا ہے؟ میں نے گزارش کی کہ پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں بھی تحریک تحفظ ناموس رسالت کی مرکزی کونسل کا حصہ ہوں اور اس حوالے سے میرا موقف وہی ہے جو ملک کے اکابر علماء کرام کا قیام پاکستان کے بعد سے مسلسل چلا آرہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب یہ سوال اٹھاکہ پاکستان میں نفاذِ اسلام کس فرقے کے مسلک اور فقہ کے مطابق ہوگا اور اس سلسلہ میں فکری، کلامی اور فقہی اختلافات کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اس سوال کے جواب کے لیے علامہ سیدسلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام نے متفقہ ۲۳ نکات پیش کرکے اس سوال اور اعتراض کا منہ بند کردیا اور بتایا کہ تمام تر اعتقادی اور فقہی اختلافات کے باوجود پاکستان میں آباد تمام مذہبی مکاتب فکر دستوری بنیاد اور قانونی نظام پر متفق ہیں اور ایک متفقہ دستوری ڈھانچہ انہوں نے پیش کردیا جس میں دیگر مکاتب فکر کے ساتھ اہل تشیع کے ذمہ دار علماء کرام بھی شریک تھے۔
۱۹۵۲ء میں تحریک ختم نبوت کے لیے تمام مکاتب فکر کو پھر سے جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور آل پارٹیز ایکشن کمیٹی قائم کی گئی تو اس میں بھی اہل تشیع کی نمایندگی موجود تھی جبکہ مولانا ابوالحسنات قادریؒ اور امیرشریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ تحریک کی قیادت کررہے تھے۔
۱۹۷۴ء میں محدث العصر حضرت علامہ سیدمحمد یوسف بنوریؒ کی قیادت میں کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تشکیل پائی اور اس کی جدوجہد سے قادیانیت کو پارلیمنٹ کو غیرمسلم اقلیت کا درجہ دلوایا تو اس کی قیادت میں بھی اہل تشیع موجود تھے۔
۱۹۷۷ء میں ملک میں نفاذاسلام کے لیے تحریک نظام مصطفی کی جدوجہد حضرت مولانا مفتی محمودؒ کی سربراہی میں میدان میں آئی اس کی قیادت میں بھی شیعہ راہ نما موجود تھے۔
۱۹۹۸ء میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد نوراللہ مرقدہ کی سربراہی میں ایک بار پھر کل جماعتی مجلس عمل کا احیاء عمل میں لایا گیا تو اہل تشیع اس کی قیادت میں موجود تھی، بلکہ نائب صدر کے منصب پر ایک شیعہ راہ نما فائز تھے۔
اب جبکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی میزبانی اور امیر مجلس حضرت مولانا عبدالمجیدلدھیانوی دامت برکاتہم کی رہ نمائی میں تحریک تحفظ ناموس رسالت وجود میں آئی ہے تو ماضی کے اسی تسلسل میں شیعہ رہنماؤں کو اس کی ہائی کمان میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل متحدہ مجلس عمل میں بھی اہل تشیع کے دیگر مکاتب فکر کے ساتھ قیادت کا حصہ رہ چکے ہیں، اس طرح دینی تحریکات کے حوالے سے قیام پاکستان کے بعد سے اب تک جو روایت اور تسلسل چلا آرہا ہے، وہ بدستور قائم ہے اور یہ دراصل سیکولر حلقوں کے اس اعتراض یا الزام کا عملی جواب ہے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص، ملک میں اسلام اور شریعت کی حکمرانی کے بارے میں ملک کے مذہبی مکاتب فکر پوری طرح متفق اور پاکستان میں نفاذ اسلام فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں بلکہ متفقہ قومی مسئلہ ہے۔
ایک موقع پر بعض دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے والدمحترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفرازخان صفدرؒ کا موقف اور طرزعمل کیا تھا؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ انہوں نے اثناء عشری اہل تشیع کی تکفیر پر’ ’ارشاد الشیعہ‘‘ کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے، میں نے گزارش کی کہ انہوں نے ’’ارشادالشیعہ‘‘ تصنیف فرمائی اور اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ صرف ان کا موقف نہیں بلکہ یہ تو اہل سنت کا موقف ہے اور خود ہمارا موقف بھی اثنا عشری اہل تشیع کی حد تک یہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان تمام تحریکات کا حصہ رہے ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفرازخان صفدرؒ اور عم محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمیدسواتیؒ اور دیگر بزرگ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں شریک ہوئے ہیں، جلوسوں کی قیادت کی، مشترکہ اجتماعات میں شرکت کرتے رہے ہیں اور دونوں گرفتار بھی ہوئے ہیں۔حضرت والدصاحبؒ کم وبیش دس ماہ، حضرت صوفی صاحبؒ نے تقریباً چھ ماہ اس تحریک میں جیل کاٹی ہے۔ ۷۴ء کی تحریک ختم نبوت میں دونوں حضرات سرگرمی کے ساتھ شریک ہوتے رہے، مشترکہ اجتماعات میں خطاب کرتے رہے ہیں اور جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں حضرت مولانا سیدمحمد یوسف بنوریؒ کی صدارت میں منعقد ہونے والا وہ تاریخی جلسہ تحریکی تاریخ کا حصہ ہے جس میں دوسرے مکاتب فکر کے اکابر علماء کرام کے علاوہ شیعہ راہ نماؤں نے بھی خطاب کیا تھا بلکہ یہ واقعہ بھی تاریخی اہمیت کا حاصل ہے کہ جلسہ کے بعد جب پولیس نے علامہ علی غضنفر کراروی کو جلسہ گاہ سے نکلتے ہی گرفتار کرلیا تو آغاشورش کاشمیری نے نہ صرف اپنے خطاب کے دوران شدید احتجاج کیا بلکہ پولیس چوکی کالوگوں کے ہجوم کے ساتھ محاصرہ کرلیا اور کراروی صاحب کو رہا کرکے وہاں سے واپس ہوئے۔
۷۷ء کی تحریک نظام مصطفی میں گوجرانوالہ میں حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی نے مشترکہ عوامی جلوس کی قیادت کی اور گکھڑ میں حضرت والد محترم جلوسوں کی قیادت کرتے رہے اور ان کا یہ تاریخی واقعہ بھی اسی تحریک کا ہے کہ فیڈرل فورس کے کمانڈر نے اس کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں لکیر کھینچ کر اعلان کیا کہ جو شخص اس لائن کو عبور کرے گا، اسے گولی مار دی جائے گی، یہ سن کر حضرت والدمحترمؒ نے اپنے رفقاء استاذ محترم حضرت مولانا محمد انور صاحب مدظلہ اور حاجی سیدڈار صاحب مرحوم کے ہمراہ یہ کہہ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے لائن کراس کی کہ ’’مسنون عمر پوری کرچکا ہوں اور اب شہادت کی تمنا رکھتا ہوں۔‘‘ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر فیڈرل سیکورٹی فورس کی رائفلیں سرنگوں ہوگئیں اور جلوس پوری شان وشوکت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔ اپنی زندگی کے آخری دس سال وہ بستر علالت پر رہے، لیکن اس دوران متحدہ مجلس عمل تشکیل پائی تو انہوں نے دونوں الیکشنوں میں متحدہ مجلس عمل کے امیدواروں کی حمایت کی اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین فرمائی۔ بعض حضرات نے اس سلسلہ میں تحفظات کا بھی ان کے سامنے اظہار کیا، مگر ان کا موقف وہی رہا۔
میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ کسی کو مسلمان، منافق یا کافر قرار دینے کا مسئلہ اپنی جگہ پر ایک دینی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قومی ضروریات اور معاشرتی روابط ومعاملات کا ایک مستقل دائرہ ہوتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ ان دونوں کا لحاظ رکھا ہے۔ حضرت والدمحترمؒ اور حضرت صوفی صاحبؒ کا زندگی بھر یہ معمول رہا ہے کہ وہ بہت سے معاملات پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے اور رائے بھی دیتے تھے، لیکن جب کوئی اجتماعی فیصلہ ہوجاتا تھا تو اسے نہ صرف قبول کرلیتے تھے بلکہ اس کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ خود میرا معمول بھی بحمداﷲ تعالیٰ یہی ہے کہ بعض معاملات پر اپنی مستقل رائے رکھتا ہوں، اس کا اظہار بھی کرتا ہوں اور کوئی مناسب موقع ہوتو اس پر بحث ومباحثہ سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن عملاً وہی کرتا ہوں جو اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے اور جمہور اہل علم کا موقف ہوتا ہے، رائے کے حق سے میں کبھی دست بردار نہیں ہوا، لیکن اپنی رائے کو حتمی قرار دے کر جمہور اہل علم کے موقف کے سامنے اڑنے سے ہمیشہ گریز کیا ہے اور اسے کبھی حق اور صواب کا راستہ نہیں سمجھا۔
میری طالب علمانہ رائے میں اسلام، کفر اور نفاق کی بحث کے باوجود معاشرتی معاملات اور اجتماعی روایات کو الگ دائرے میں رکھنا چاہیے اور اس سلسلہ میں دورنبویؐ میں ہمارے لیے مثال موجود ہے۔ عبداللہ بن أبی اور اس کے منافق ساتھیوں کو جن کی تعداد غزوۂ احد کے موقع پر تین سو کے لگ بھگ بیان کی جاتی تھی، قرآن کریم کی نص قطعی میں ’’کافر‘‘ قرار دیا گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ’’وماہم بمؤمنین‘‘ ،وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادات میں شریک ہوتے رہے ہیں، غزوات میں اپنی تمام تر غلط حرکات کے باوجود شامل ہوتے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انہیں قتل نہ کردیا جائے؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ’’نہیں! اس سے یہ تاثر پھیلے گا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کردیتے ہیں‘‘، اس لیے کہ دنیا کو وہ مسلمانوں کا حصہ ہی نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ منافقین نے ایک موقع پر الگ مسجد بناکر خود کو عمومی معاشرے سے الگ کرنا چاہا تو قرآن کریم نے اسے ’’مسجدضرار‘‘ قرار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کووہاں جانے سے منع کردیا۔ وہ مسجد گرادی گئی اور مصلحت اسی میں سمجھی گئی کہ منافقین کو ان کے کفر کے باوجود معاشرتی طور پر الگ ہونے سے روکا جائے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اکابر کے فیصلوں پر حسب سابق اعتماد کیا جائے۔
قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت (۲)
محمد یونس قاسمی
مولانا زاہد الراشدی مدظلہ نامور عالم دین اور اسلامی سکالر کی حیثیت سے معروف ہیں۔ پاکستان شریعت کونسل کے سربراہ، الشریعہ اکیڈمی گوجرانوالہ کے ڈ ائریکٹراور جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ کے شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ روزنامہ اسلام کے مستقل کالم نگار اور متعد د کتب و رسائل کے مصنف بھی ہیں۔ عالم اسلام میں پائے جانے والے مختلف عنوانات پر اختلافات کے خاتمے کے لیے محققانہ گفتگو اور مکالمہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ مولانا موصوف نے روزنامہ اسلام میں ۱۱ فروری کو ’’اکابر کے فیصلوں پر اعتماد کیا جائے‘‘ کے عنوان سے ایک فکر انگیز کالم تحریر فرمایا ہے جس میں انہوں نے تحریک تحفظ ناموس رسالت میں اہل تشیع کی شمولیت کے متعلق اٹھائے جانے والے بعض سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اور یہ اپیل کی ہے کہ اکابر پر مکمل اعتماد کیا جائے اور ان کے فیصلہ جات کا احترام کیا جائے۔ اکابر پراعتماد اور ان کے فیصلہ جات کا احترام یقیناہم سب پر لازم ہے اور ان فیصلہ جات سے کسی صورت بھی روگردانی نہیں ہونی چاہیے، مگر مشکل اس وقت پیش آتی جب اکابر کی طرف سے نئے فیصلہ جات سامنے آتے ہیں اور سابقہ فیصلہ جات کے ذریعے ایک راستہ اور منزل متعین کر کے جن لوگوں کو اس راستے پر چلایاگیا تھا، انہیں اعتماد میں بھی نہیں لیا جاتا۔ اگر سابقہ فیصلہ جات کی ضرورت اب ختم ہوگئی ہے اوران پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا، وہ پورا ہوچکا ہے اور وہ تمام فیصلے اب کالعدم ہوگئے ہیں تو اس بات سے آگاہ کرنا اور اعتماد میں تو لیا جانا چاہیے۔
تحریک تحفظ ناموس رسالت یا اس طرح کی دوسری تحاریک میں قومی ضروریات کو مدنظر رکھ کر اس میں اثناعشری اہل تشیع کی شمولیت کو جائز ثابت کرنے کے لیے قیام پاکستان سے لے کر اب تک مختلف چلائی جانے والی تحاریک کے حوالے دے کر بڑے خوبصورت انداز میں مولانا زاہد الرشدی صاحب نے اپنا مؤقف بیان کیا ہے، مگر ان چند ایک واقعات کے علاوہ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ سے کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں کرسکے جس سے یہ ثابت ہو کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف چلائی جانے والی تحاریک میں خود منکرین ختم نبوت کو بھی شامل کیا گیا ہو۔ حضرات تابعین کے دور سے یہ فتاویٰ اور فیصلے چلے آرہے ہیں کہ خاتم المعصومین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر، صحابہ کرامؓ کے ایمان کا انکار کرنے والے، شیخینؓ کی صحابیت کا انکار کرنے والے اورقرآن کریم میں تحریف کے قائل لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر اہل تشیع اثنا عشری کے متعلق انہی عقائد باطلہ کی وجہ سے وقت کے مقتدر اور محقق علمائے کرام نے تکفیر کا فیصلہ صادر فرمایا اور خود مولانا زاہد الراشدی صاحب اور ان کے والد گرامی امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ کا بھی یہی فیصلہ اور فتویٰ ہے، جیساکہ مولانا راشدی صاحب کے مذکورہ کالم اور امام اہل سنت ؒ کی کتاب ’’ارشاد الشیعہ‘‘ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت میں اس وقت جتنے اکابر علمائے کرام شامل ہیں، ان سب کے یہی عقائد ونظریات ہیں کیونکہ ان سب حضرات نے اہل تشیع کے متعلق جاری ہونے والے متفقہ فیصلہ پر اپنے تائیدی دستخط ثبت فرمائے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اس متفقہ فیصلہ کے بعد ایک اور فتویٰ (جسے متفقہ فیصلہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گاکیونکہ اس فتویٰ پر پاکستان،بنگلہ دیش اور برطانیہ کے اکابر علماء ومفتیان کے علاوہ سینکڑوں جید علماء کرام ومفتیان عظام کے دستخط موجود ہیں) چند سال قبل اس وقت سامنے آیا جب اہل تشیع اثنا عشری کو مسلمان قرار دے کر ایک سیاسی مذہبی اتحاد ’’متحدہ مجلس عمل‘‘اور اہل تشیع اثنا عشری کے تعلیمی اداروں کو دینی ادارے قرار دیتے ہوئے دینی مدارس کے اتحاد ’’اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ‘‘ میں شامل کیا گیا۔ اس فتویٰ میں پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں یہ لکھا گیا ہے کہ ’’ان کے ساتھ تمام تعلقات اور دیگر مراسم اسلامیہ رکھنا ہرگز جائز نہیں کیونکہ یہ لوگ اس قسم کے تعلقات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں،اپنے غلط عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ان تعلقات کو بطور دلیل پیش کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے مذہبی اداروں اور تنظیموں کو دینی واسلامی کہنے سے اپنے ایمان کو خطرہ ہے۔‘‘ یادرہے کہ تحریک تحفظ ناموس رسالت میں اہل تشیع اثنا عشری کی تنظیم کو اسلامی تنظیم قرار دے کر اتحاد میں شامل کیا گیا ہے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک چلائی جانے والی تمام تحاریک میں اہل تشیع شامل رہے ہیں تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایسے ہر اتحاد اور ہر واقعہ پر کم ازکم دس، دس صفحے لکھے جاسکتے ہیں لیکن انتہائی ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان تمام’’ حقائق‘‘ سے شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمدؒ ، فقیہ العصر حضرت مفتی عبد الستارؒ ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خاں صفدرؒ ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر، شیخ الحدیث مولاناعبدالمجید لدھیانوی، مفتی عبد القیوم ہزاروی، شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ، شیخ الحدیث مفتی غلام قادر ؒ دارالہدیٰ ٹھیڑی اور حضرت مفتی محمدزرولی خان سمیت دیگرسینکڑوں اکابر علماء اور مفتیان عظام واقف نہ تھے؟ کیونکہ ان تمام اکابر نے علامہ علی شیر حیدری شہیدؒ کے موقف کی تائید اس وقت فرمائی جب یہ تمام تاریخی واقعات موجود تھے۔ اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں ۲۹، ۳۰، ۳۱؍اکتوبر ۱۹۸۶ء کو عالمی اجلاس برائے تحفظ ختم نبوت منعقد ہوا تھاجس میں باقاعدہ ایک قرارداد پاس کی گئی جس کا متن کچھ یوں ہے کہ ’’یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ شیعہ اثنا عشری مسلک جو فی زمانہ دنیا کے شیعوں کی اکثریت کا مسلک ہے اور ایران میں اس مسلک کے ماننے والوں کے ذریعے ماضی قریب میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، جس کو اسلامی انقلاب کہہ کر عالم اسلام کو زبردست دھوکہ دیا جاریا ہے، اس مسلک کا بنیادی عقیدہ، عقیدہ امامت براہ راست ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی بنا پر حضرت شاہ ولی اللہؒ نے صراحت کے ساتھ ان کی تکفیر کی ہے۔لہٰذا یہ اجلاس برائے تحفظ ختم نبوت اعلان کرتاہے کہ یہ مسلک موجب کفر اور ختم نبوت کے خلاف پرفریب بغاوت ہے۔ نیز یہ اجلاس تمام اہل علم سے اس فتنہ کے خلاف سرگرم عمل ہونے کی اپیل کرتا ہے۔‘‘ (ازاداریہ ماہنامہ ’’دارالعلوم‘‘ دیوبند، بابت ماہ جنوری ۱۹۸۷)
میری گزارشات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اکابر علماء کرام کے فیصلوں یا فتاویٰ پر اعتماد سب کرتے ہیں، چند ایک ایسے ہیں جن کے لیے ان فیصلوں میں تمیز کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ وہ کس فیصلے پر اعتماد کریں۔اہل تشیع اثنا عشری کے متعلق اکابر علماء کرام کے دو متفقہ فیصلے موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں کوئی اورفیصلہ کرنے سے قبل ان دو فیصلوں کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے اور کم ازکم اکابر کے ان دوفیصلوں کی روشنی میں جدوجہد کرنے والی جماعتوں اور شخصیات بلکہ جنھیں اکابر نے یہ جدوجہد کرنے پر آمادہ کیا تھا، ان کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے۔ آج جنھیں اکابر کے فیصلوں پر اعتماد نہ کرنے کا طعنہ دیا جا رہا ہے، وہ تو بطریق اولیٰ اکابر کے ان فیصلوں پر اعتماد کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کے احترام میں پانچ عظیم المرتبت قائدین، دو ہزار پانچ سوسے زائد افراد کی قربانی پیش کرچکے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے قبل شاید ہی تاریخ اسلامی میں کوئی ایسی تحریک موجود ہو جس نے اکابر کے فیصلوں پر اعتماد کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی ہو۔ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے والوں کے امین اور وارث ہوں، وہ کیسے اپنے قائدین اور کارکنوں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور کیسے اکابر کے ان فیصلوں سے منحرف ہوسکتے ہیں؟ مگر پھر بھی شکوہ انہی سے کیا جارہا ہے۔ ان حالات میں موجودہ اکابر علماء کرام سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے مل بیٹھ کر اتفاق رائے سے فیصلے کریں اور نئے فیصلے کرنے سے قبل اپنے سابقہ فیصلہ جات کو مدنظر رکھیں تاکہ کہیں کو ئی اختلافی صورت حال پیدا نہ ہوسکے۔
قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت (۳)
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
راقم الحروف نے مختلف دوستوں کے سوالات پر تحریک تحفظ ناموس رسالت کی قیادت میں اہل تشیع کی شمولیت کے مسئلے پر اپنے موقف کی وضاحت کی تھی جو روزنامہ اسلام میں ۱۱؍ فروری ۲۰۱۱ء کو ’’نوائے حق‘‘ کے عنوان سے میرے مستقل کالم کی صورت میں شائع ہوئی۔ اس پر محترم جناب مولانا محمد یونس قاسمی نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے جو مذکورہ کالم کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ مولانا قاسمی کی شکایت یہ ہے کہ اکابر کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں جبکہ میں نے اس کالم میں ہی اس کے بارے میں عرض کر دیا تھا کہ کسی کو کافر قرار دینے یا مسلمان تسلیم کرنے کا دائرہ الگ ہے اور معاشرتی روابط اور مشترکہ تحریکات میں اشتراک عمل کا دائرہ اس سے مختلف ہے جس کی واضح مثال موجود ہے کہ دور نبوی میں عبد اللہ بن ابی اور اس کے ٹولے کو قرآن کریم کی نص قطعی میں کافر قرار دیے جانے کے باوجود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی طور پر انھیں الگ نہیں کیا بلکہ ان کی تمام تر خرابیوں اور غلط کاریوں کے ہوتے ہوئے بھی انھیں اجتماعی معاملات میں اپنے ساتھ شریک رکھا، اس لیے کہ انھیں معاشرتی طور پر الگ کرنے اور ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرنے میں اس دورکے حالات میں مصلحت نہیں تھی۔
ہمارے اکابر کا طریقہ بھی یہی چلا آ رہا ہے کہ کفر کے فتووں کے باوجود مشترکہ قومی معاملات اور اجتماعی تحریکات میں اہل تشیع کو اپنے ساتھ شریک رکھا ہے اور اس میں کوئی تعارض اور الجھن کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے متفقہ ۲۲ نکات، ۵۳ء کی تحریک ختم نبوت، ۱۹۷۳ء کے دستور، ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت، ۱۹۷۷ء کی تحریک نظام مصطفی اور ۱۹۸۴ء کی تحریک ختم نبوت کا حوالہ مذکورہ کالم میں دیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ اس تسلسل میں چند اور تحریکات کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔
- بھارت میں مسلمانوں کے شرعی خاندانی قوانین کے تحفظ کے لیے ’’آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ‘‘ کا مشترکہ پلیٹ فارم موجود ہے جس کے پہلے سربراہ حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ ، دوسرے سربراہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ ، تیسرے سربراہ حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمیؒ تھے جبکہ اب اس کے سربراہ حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی مدظلہ ہیں اور اہل تشیع اس بورڈ کا نہ صرف مسلسل حصہ ہیں بلکہ ممتاز شیعہ علما اس کے مرکزی عہدہ دار بھی چلے آرہے ہیں۔
- ایران میں اہل سنت کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کے تلامذہ میں سے تھے، ایرانی انقلاب کے بعد اس کی مرکزی کونسل اور دستور ساز اسمبلی کے ممبر رہے ہیں اور ایرانی دستور کی تشکیل میں ان کا اہم کردار ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی اور دوسرے علماء کرام کے ساتھ مجھے ۱۹۸۷ء میں ایران جانے کا موقع ملا تو ہم نے ایران میں حضرت مولانا عبد العزیز سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ انھوں نے ایرانی انقلاب اور دستور میں اپنے کردار کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا، البتہ یہ شکایت کی کہ اب ایرانی راہ نماؤں کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور وہ ان کی باتوں پر پہلے کی طرح توجہ نہیں دیتے۔
- افغانستان میں روسی استعمار کے خلاف جہاد میں اہل سنت کی نصف درجن کے لگ بھگ جہادی تنظیموں کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کی ’’حزب وحدت‘‘ بھی جہاد افغانستان کا حصہ رہی ہے اور ان تنظیموں کے درمیان اس دور میں اشتراک وتعاون بھی رہا ہے۔
- دینی مدارس کے تحفظ کے لیے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کے وفاقوں کے اتحاد ’’اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ‘‘ میں وفاق المدارس الشیعہ شامل ہے جس کا ذکر محترم مولا نا محمد یونس قاسمی نے بھی اپنے مضمون میں کیا ہے۔
اس لیے مولانا محمد یونس قاسمی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اصل الجھن انھیں صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ دونوں الگ الگ دائروں میں فرق نہیں کر پا رہے۔ اگر اس فرق کو وہ سنجیدگی سے محسوس کر لیں تو انھیں اکابر کے طرز عمل میں نہ کوئی تضاد نظر آئے گا اور نہ ہی یہ شکایت ہوگی کہ بزرگوں نے پہلے فیصلوں کے بعد نیا فیصلہ کرنے میں متعلقہ دوستوں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اکابر کے فیصلے فتووں کے دائرے میں مسلسل وہی چلے آ رہے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں اور معاشرتی روابط اور دینی تحریکات کے دائرے میں بھی ان کے فیصلوں کے تسلسل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ صرف دائروں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کسی دوست کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔
۲۹۵ سی : اقلیتوں کا نقطہ نظر
ڈاکٹر کنول فیروز
یادش بخیر! ۲۹۵۔سی کے حوالے سے ہم پہلے بھی اپنی نپی تلی رائے دے چکے ہیں کہ پاکستان کی اقلیتیں خصوصاً مسیحی اس کی روح اور نفاذکے قطعی خلاف نہیں کیونکہ اس قانون کا نفاذ واطلاق اہل اسلام کے دینی اور قلبی جذبات واحساسات کا انتہائی حساس مسئلہ ہے اور شایدا سی لیے جب پہلے پہلے قومی اسمبلی نے اس کی منظوری دی اور پھر بعدا زاں شریعت کورٹ نے اس جرم کی کم از کم سزا موت قرار دی تو اقلیتی حلقوں نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ اس وقت کے اقلیتی ایم این اے عمانوئیل ظفر نے کریمنل لاء امینڈمینٹ بل ۱۹۸۶ء کی منظوری کے دوران جو وزیرمملکت برائے عدل وپارلیمانی امور میر نواز خان سومرو نے پیش کیا تھا، اس قانون کو متفقہ طور پر پاس کرنے پر اسپیکر قومی اسمبلی کو مبارک باد بھی دی، کیوں کہ ظاہر ہے کہ ۹۵ فی صد سے بھی زائد مسلم اکثریت کے ملک میں کوئی پاگل اور فاتر العقل شخص ہی دانستہ ۲۹۵۔سی کے جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے یا اس کی مخالفت کر سکتاہے او ر غالباً یہی وجہ ہے کہ اس وقت وطن عزیز کے کسی حلقے کی طرف سے بھی اس قانون کی مخالفت نہیں کی گئی، کیوں کہ بادی النظر میں دیکھا جائے تو صحیح الدماغ شخص، وہ خواہ کسی مذہب و عقیدہ یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ صورتحال گھمبیر اس وقت ہوئی جب اس قانون کی آڑ میں ذاتی، مسلکی اور سیاسی دشمنیوں اور اختلافات کے تحت کثرت سے مقدمات درج ہونے لگے اور پھر اسے مذہبی سے زیادہ جذباتی اور سیاسی مسئلہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی۔ ہم آج بھی صدق دل سے ۲۹۵۔سی کی حقیقی روح کے حق میں ہیں۔ کسی بھی شخص کو بانی اسلام رسول کریم کی شان میں گستاخی کی معافی نہیں دی جا سکتی۔ خواہ کوئی بھی اس کا مرتکب ہو یا کسی کے بھی مذہبی جذبات مجروح کرنے کا باعث ہو، اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہماری تو صرف یہ گزارش ہے کہ آج تک جتنے بھی مقدمات اس قانون کے تحت درج ہوئے، ان کے ملزموں کو وطن عزیز کی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے باعزت بری کر دیا، کیوں کہ ان پر یہ الزام جھوٹا اور ذاتی یا مسلکی دشمنی ثابت ہوا، لہٰذا اسی بنیاد پر مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس قانون میں ترمیم کر کے جھوٹا الزام لگانے والوں کو بھی یہی سزا دی جائے، کیوں کہ لامحالہ یوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ الزام لگانے والوں اور استغاثہ نے جو کہانی گھڑی تھی، اس کے تحت وہ خود توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی ترمیم کا مطالبہ اس قانون کی روح کو ختم کرنانہیں، بلکہ اس قانون کے غلط اور ناجائز استعمال کو روکنا اور بے گناہ کو موت کے پھندے سے بچانا ہے اور دنیا کا کوئی انصاف پسند شخص اور خدائے برحق پر ایمان رکھنے والا کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی بے گناہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے یا اسے سرعام قتل کر دیاجائے، لہٰذا اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ترمیم کا مطالبہ اقلیتوں کا ہی نہیں بلکہ سول سوسائٹی، روشن خیال حلقوں بلکہ جید علماء کرام بھی اس کے حق میں ہیں کہ کسی بے گناہ کو ناکردہ گناہ کی سزا نہیں ملنا چاہیے۔
گورنر سلمان تاثیر بھی اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے اور کسی بے گناہ کو سزا نہ دینے اورحق وانصاف کا بول بالا کرنے کی پاداش میں قتل کر دیے گئے۔ اگر چہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنر سلمان تاثیر کی نیک نیتی اور انسانی ہمدردی کے جذبات اپنی جگہ قابل تحسین ہیں، لیکن ان کا آسیہ بی بی کی سیشن کورٹ ننکانہ سے سزائے موت کے فیصلہ کے خلاف صدر سے رحم کی اپیل بہت قبل از وقت تھی۔ ابھی تو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں محترمہ آسیہ بی بی کے بارے میں کیس موجود تھا اور ہے۔ اسی طرح ہم پاپائے اعظم بینی ڈکٹ اور یورپی یونین کی پارلیمنٹ کی طرف سے آسیہ بی بی کی رہائی اور ۲۹۵۔سی کی منسوخی کے مطالبہ کو بھی بے محل، بے موقع اور لاحاصل سمجھتے ہیں، کیوں کہ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ آسیہ بی بی کی اپیل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی جا سکتی ہے۔ اس صورت حال میں ان بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے جب کہ موجودہ معروضی صورتحال میں ٹھنڈے دل سے مذہبی یا جذباتی نہیں بلکہ متوازن فکر، اعتدال پسندی اور خالص انسانی نقطہ نظر سے اس مسئلہ کو حل کرنے اور طرفین کو قائل کرنے کی ضرورت ہے۔
مندرجہ بالا حقائق وواقعات کی روشنی میں ہماری گزارش ہے کہ عموماً مقدمہ کے اندراج اور سیشن جج کی حد تک ۲۹۵۔سی کے ملزموں کو سزادینے کے لیے پولیس اور عدالت پر مقامی دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سیشن کورٹ ساہیوال میں ایوب مسیح کا کیس بھی ہے جسے مقامی پریشر کی بنیاد پر سیشن کورٹ سے سزا ئے موت دی گئی جس کے فیصلے کے خلاف ڈاکٹر جان جوزف پی ایچ ڈی کا تھولک بشپ آف فیصل آباد نے سیشن کورٹ کے سامنے احتجاجاً خود کشی کر لی تھی، لیکن تاریخ گوا ہ ہے کہ ایوب مسیح کو سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا تھا۔ اس موقعہ پر بشپ ڈاکٹر جان جوزف کا خود کشی کا اقدام بھی ’’جذباتی‘‘ اور قبل از وقت سمجھا گیا۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ سیشن کورٹ کا پریشر مزید سنگین صورت اختیار کر گیا جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عارف اقبال حسین بھٹی نے توہین رسالت کے ملزموں سلامت مسیح اور منظور مسیح کو مقامی لاء جیورسٹ کی معاونت سے کیس کی مکمل چھان بین کے بعد بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا جب کہ اس کا ساتھی منظور مسیح عدالت کے فیصلے سے قبل ہی ماورائے عدالت، تاریخ پیشی بھگتنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے باہر گیٹ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ بعدا زاں اس حق وانصاف پر مبنی فیصلہ کی ’’پاداش‘‘ پر جسٹس عارف اقبال بھٹی کو ان کے چیمبر، نر نر روڈ لاہور پر دن دیہاڑے اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جس وقت ملکہ برطانیہ لاہورکے دورے پر مال روڈ پر گزر رہی تھی۔ جب صورت حال یہ ہو تو پھر کون جج حق وانصاف کے تحت بے گناہ ملزموں کے حق میں فیصلہ کرنے کا رسک لے گا؟ جب کہ جھوٹا مقدمہ درج کرانے والوں کے لیے قانون میں کوئی سزا نہیں ہے۔ اس طرح تو جب جس کا جی چاہے، اپنے ذاتی مخالف کو تختہ دار پر پہنچا دے، اس کابال بھی بیکا نہ ہوگا۔ پھر یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ -295سی کا کیس درج کرتے وقت مکمل چھان بین، حزم واحتیاط اور تحقیق صحت مقدمہ کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے قانون سازی ہونا چاہیے کیوں کہ اس الزام کے بعد ملزم اگر عدالت سے بری بھی ہو جائے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی اور اسے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکرہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے گزشتہ چیئرمین کے دور میں خود اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس میں اس نوع کی ترمیم کی سفارش کر چکی ہے جس کی اس وقت کسی نے مخالفت نہ کی، بلکہ قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے حوالے سے ان سفارشات کو سراہا گیا تھا۔
۲۹۵۔سی کے غلط استعمال کے خلاف جب بھی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہرقانون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قتل کی دفعہ ۳۰۲ اور دیگر پینل کوڈ کے بڑے بڑے جرائم سے متعلق قوانین کا حوالہ دیاجاتاہے اور کہا جاتا ہے کہ کیا ان کو بھی منسوخ کر دیا جائے یا ان میں بھی ترمیم کی جائے؟ بظاہر یہ دلیل بذات خود خاصی وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن ۲۹۵۔سی اور ۳۰۲ اور دیگر سنگین دفعات میں خاصا فرق ہے۔ اول یہ کہ ۳۰۲ میں سزائے موت کے علاوہ عمر قید اور قصاص ودیت کے تحت معافی کی بھی گنجائش ہے جب کہ ۲۹۵۔سی میں کم از کم سزا موت ہے اور اس میں کوئی معافی یا تلافی کی گنجائش نہیں۔ پھر جب یہ الزام کسی غیر مسلم پر لگایاجاتا ہے تو نہ صرف وہ شخص ماورائے عدالت بھی قابل گردن زدنی سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کے خاندان اور بعض حالتوں میں اس کی پوری کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے جس کی مثال گوجرہ اور کوریاں کا المناک واقعہ ہے جس میں قرآن پا ک کی بے حرمتی کے ایک شخص پر جھوٹے الزام کی بنیاد پر پوری بستی کو نذر آتش کر دیا گیا جس میں کئی جانیں اور مقدس بائبل کی کئی جلدیں بھی جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اسی طرح شانتی نگر، سانگلہ ہل، باہمنی والہ قصور کے تازہ واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں جس کی عدالتی تحقیقات میں یہ الزام کسی پر ثابت نہ ہو سکا، لیکن جھوٹا الزام لگانے والے آج بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ اس جھوٹے الزام کی پاداش میں کتنے گھر تباہ وبرباد ہوئے، کتنے مذہبی جذبات مجروح ہوئے، اس کی ہائی کورٹ کے جج نے تحقیقات بھی کیں جسے آج تک منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ لیکن نہ تو شانتی نگر، نہ ہی سانگلہ ہل اور نہ ہی گوجرہ کے المناک واقعات میں ملوث ملزموں کو سزا ملی جب کہ جو گرجہ گھر اور عبادت گاہیں جلاد ی گئیں، بائبل مقدس کو خاکستر کر کے اس کی بے حرمتی کی گئی، لوگوں کی املاک تباہ ہوئیں اور عزت وناموس پامال ہوئی اور سب سے بڑھ کرجو وطن عزیز کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی اور خود مذہب اسلام پر جو حرف آیا، اس کے مرتکبین آج بھی سزا سے ماورا ہیں۔ اس تمام تفصیل سے صرف اتنی عرض ہے کہ ۲۹۵۔سی کے غلط محرکات، جھوٹے مقدمات اور الزامات کی سنگینی کو واضح کریں اور حق وانصاف کے ان تمام تقاضوں اور دعووں کے حوالے سے یہ گزارش کریں، جن پر تمام اہل مذاہب کا اتفاق ہے کہ بے گناہ اور معصوم جانوں کو ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس قانون کے تحت صرف غیر مسلم ہی ستم رسیدہ نہیں بلکہ کئی اہل اسلام بھی اس کے تحت ذاتی دشمنی، مسلکی اور سیاسی اختلافات کی نذر ہو چکے ہیں اور آج بھی پابند سلاسل ہیں، جب کہ کوئی مسلمان گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتا جس کی تازہ مثال گورنر سلمان تاثیر ہیں اورماضی قریب میں گوجرانوالہ کے حافظ قرآن فاروق احمد ہیں جنہیں قرآن مجید کی توہین کے جھوٹے الزام کی پاداش میں نہایت ذلت اور تذلیل کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش کو موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا گیا جب کہ وہ قاری اور حافظ قرآن مجید بھی تھے۔ بقول علامہ اقبالؒ
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
لیکن ان کے قاتلوں کو بھی کوئی سزا نہ دی گئی۔ یوں نادانستہ طورپر جھوٹا الزام لگانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی۔ اس تمام تر بحث کے بعد ہماری علمائے اسلام سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہم ۲۹۵۔سی سمیت تمام قوانین کا اور ان کے جذبات کا تہہ دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے حق وانصاف کے مسلمہ اصولوں اور تمام بانیان دین حق کے نام پر اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی کٹر رائے پر نظر ثانی کریں اور اس قانون کے غلط اور جھوٹے الزام لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آواز بلندکریں اور توہین رسالت کے مرتکب کاذب اور مفتری کو بھی اسی سزا کا مستحق قرار دے کر بے گناہوں اور ناکردہ گناہوں کی سزا پانے والوں کی داد رسی کا پیغمبرانہ کردار ادا کریں۔ یوں یہ امرخدائے عزوجل کی خوشنودی حاصل کرنے اور فلاح انسانیت کا باعث بھی ہوگا، خواہ اس کے لیے الگ قانون سازی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس طرح ملک وقوم مزید انتشار اور عالمی سطح پر بدنامی سے بھی بچ جائیں گے اور وطن عزیز میں تمام اہل وطن سکھ کا سانس لیں گے اور اس اقدام اور صحت مندرویے سے اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرنے والوں، جھوٹا الزام لگانے والوں اور اس الزام کے تحت قانون ہاتھ میں لینے والوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اس الزام بلکہ کسی بھی الزام کے تحت ماورائے عدالت قتل توہین انسانیت اور قتل انسانیت کے مترادف ہے، کیوں کہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیاجا سکتا کہ وہ قتل کے بدلے خود قتل کرے اور کسی بھی ملزم کو ماورائے عدالت قتل کر دے۔
مقام افسوس ہے کہ یہ روایت چل پڑی ہے، مدعی خود ہی منصف بن بیٹھے ہیں بلکہ ’’خود ذبح بھی کرے ہیں اور لیں ثواب الٹا‘‘ اور اگر یہی صورتحال رہی تو وطن عزیز میں جنگل کا قانون رائج ہونے کے امکانات ہیں۔ آج اقلیتی حلقوں میں گورنر تاثیر کے قتل کے بعد خوف وہراس، عدم تحفظ، بے اطمینانی، بے دلی اور مایوسی کی فضا پھیل گئی ہے جسے دور کرنے کے لیے ان کے تحفظات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ دیگر اہل وطن کے شانہ بہ شانہ حسب سابق ملک وقوم کی سالمیت اور استحکام کے لیے اپنا کردار بلاخوف وخطر ادا کرتے رہیں۔ امید ہے ہماری گزارشات کے حوالے سے اس مسئلہ کا مثبت حل تلاش کرنے کی طرف جلد پیش رفت ہو گی اور ارباب بست وکشاد اور علمائے کرام اسے محض مذہبی مسئلہ نہ سمجھتے ہوئے اس کے انسانی پہلوؤں پر بھی توجہ دیں گے کہ شرف انسانیت ہر دین کی بنیاد ہے۔
(بشکریہ ماہنامہ شاداب، لاہور)
مکاتیب
ادارہ
(۱)
محترم جناب عمار خان ناصر صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔
یوگندر سکند کے آپ کے والد ماجد سے سوالات اور مولانا محترم کے جوابات ارسال کرنے کا بہت بہت شکریہ!
دیوبند میں ہوئی کشمیر کانفرنس کے حوالے سے جب آپ کے رسالہ کی کسی قریبی اشاعت میں ایک مضمون شائع ہوا تھا تو آپ کو اس کی بابت کچھ لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اب اس انٹرویو میں بھی اس کا تذکرہ دیکھ کر خیال ہوا کہ سردست چند سطریں ہی آپ کی خدمت میں ارسال کر دی جائیں۔
۱۔ یہ کانفرنس جمعیۃ علماء ہند نے منعقد کی تھی، دار العلوم دیوبند نے نہیں۔
۲۔ یہ کانفرنس دار العلوم دیوبند میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ دیوبند کے ایک میدان میں ہوئی تھی۔
۳۔ اس کانفرنس کا کوئی رسمی یا غیر رسمی تعلق دار العلوم سے نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ماضی میں دار العلوم اور جمعیۃ ’یک جان دو قالب‘ جیسے بنا دیے گئے تھے، لیکن پچھلے برسوں میں جب جمعیۃ میں اختلافات ہوئے تو دار العلوم کی انتظامیہ نے دار العلوم اور جمعیۃ کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی، یہاں تک کہ جمعیۃ کے دونوں دھڑوں کے سربراہان مولانا ارشد مدنی اور مولانا عثمان صاحب کو بالترتیب دار العلوم کے اعتماد تعلیم اور نیابت اہتمام سے معزول کر دیا گیا تھا۔
۴۔ اس کاففرنس کو جمعیۃ کے ایک دھڑے نے صرف اسی لیے دیوبند میں منعقد کیا تھا تاکہ اس کو دار العلوم کی کانفرنس کہا جا سکے اور ایسا ہی ہوا۔ میڈیا نے اسے دار العلوم کی کانفرنس کہا اور یہ باور کرایا کہ یہ دار العلوم کے اندر ہوئی ہے، ورنہ اس عالمی مسئلہ پر ہونے والی کانفرنس کو ایک چھوٹے سے قصبہ میں منعقد کرانے کی کیا تک تھی؟
۵۔ دار العلوم کا اس کانفرنس اور اس کی تجاویز سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ ماضی کی روایات کے بالکل برخلاف اس کانفرنس میں دار العلوم کے ذمہ داران میں سے کوئی شریک بھی نہیں ہوا، لہٰذا اس کی بابت یہ خیال کرنا کہ یہ کانفرنس دار العلوم نے اپنے گرد وپیش کے حالات سے مجبور ہو کر منعقد کی تھی، صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان کی حکومت کا کشمیر کے سلسلہ میں جو رویہ رہا ہے، یہاں کے مسلمانوں نے ہمیشہ اس پر حکومت کی سخت تنقید کی ہے۔
۶۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یوگیندر سکند صاحب نے بھی اس کانفرنس کو دار العلوم کے اندر منعقد ہوا بتایا۔ یہ جمعیۃ کے ایک دھڑے کی سیاسی بازی گری تھی، اور کچھ نہیں۔ افسوس کہ اس حوالہ سے دار العلوم کو بے جا بدنام کیا جا رہا ہے۔
مولانا محمد الیاس نعمانی
(ماہنامہ الفرقان، لکھنو)
(۲)
محترم المقام جناب عمار خان ناصر صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
مجلہ الشریعہ کا دسمبر ۱۰ء کا شمارہ میرے سامنے ہے۔ اس میں شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد زاہد صاحب مدظلہ کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے: ’’اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور حکومت کا نیا معاہدہ‘‘۔ مجھے اس مضمون کے عنوان سے اختلاف ہے۔ چند سال قبل دینی مدارس کے پانچ بورڈوں کا مشترکہ ایک پلیٹ فارم بنا تھا جس میں مختلف چار مسالک کے دینی مدارس کے بورڈ تھے اور ایک بورڈ شیعہ مذہب کا تھا۔ ان پانچ بورڈوں کے متحدہ پلیٹ فارم کا نام ’’اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ‘‘تجویز کیا گیا۔ بندہ نے اس دور میں فیصل آباد سے شائع ہونے والے رسالہ ماہنامہ ’’خلافت راشدہ‘‘ میں اس عنوان پر بہت کچھ لکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہؓ کے سربراہ علامہ علی شیر حیدری شہیدؒ اورسپاہ صحابہؓ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خادم حسین ڈھلوں نے اس عنوان پر ان تھک محنت کی اور اس اتحاد کے ذمہ داران سے مسلسل ملاقاتیں کی جس کے نتیجہ میں لفظ ’’دینیہ‘‘ اس فورم کے نام سے الگ ہوگیا۔اب اس فورم کانام صرف’’ اتحاد تنظیمات مدارس‘‘ ہی ہے جس کی تصدیق اس فورم کے ذمہ داران بھی کرتے ہیں اور ان کا چھپنے والا لٹریچر بھی اسی نام سے چھپتا ہے جس میں’’ صرف اتحاد تنظیمات مدارس‘‘ ہی لکھا جاتا ہے۔
اہل تشیع کے عقائد کفریہ کی بنا پر تمام علماء محققین کا شیعہ کی تکفیر پر اجماع اور اتفاق ہوچکا ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: امداد الفتاویٰ،جلد ۴صفحہ ۵۸۴ اور احسن الفتاویٰ،جلد ۱صفحہ ۷۳ تا ۱۰۶،نیز ’’خمینی اور اثنا عشریہ کے متعلق علماء کرام کا متفقہ فیصلہ‘‘بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔اس لیے جب ان کے متعلق سب کچھ معلوم ہو اور ان کے کفریہ عقائد ظاہر ہوچکے ہوں، اس کے بعد بھی ان کے مذہبی اداروں اور تنظیموں کو دینی واسلامی کہنا اپنے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوسکتاہے،بالخصوص جبکہ اہل تشیع اس قسم کے تعلق اور ایسے اتحاد سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے غلط عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ایسے تعلقات اور ایسے اتحادکو دلیل کے طور پر پیش کرکے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب میری تیار کی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اکابر علماء کرام کے ایک فتویٰ کی رو سے میں نے یہ سب باتیں لکھی ہیں اور اس فتویٰ پر ملک کے جیدمفتیان اور علمائے کرام کے دستخط موجود ہیں۔اس لیے میری آنجناب کے ذریعہ سے حضرت مفتی زاہد صاحب مدظلہ سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ ’’اتحاد تنظیمات مدارس ‘‘کے ساتھ لفظ دینیہ لکھنے سے گریز کریں تاکہ دشمنان اسلام کو اس سے غلط فائدہ اٹھانے اور عوام کو اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا موقع نہ مل سکے۔
امید ہے کہ حضرت مفتی صاحب میری ان معروضات پر ضرور غور فرمائیں گے۔
محمد یونس قاسمی
(۳)
مکرمی ومحترمی شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب زید مجدکم، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان
ومولانا محمد حنیف جالندھری صاحب، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان
ودیگر ارکان مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
باعث تحریر یہ کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اجلاس منعقدہ ۳؍ صفر المظفر ۱۴۳۲ھ میں جو فیصلے ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے:
’’دوران امتحان نقل اورمتبادل کے رجحان کے سدباب کے لیے داخلہ فارم کے ساتھ طالب علم کی تین تازہ تصاویر جو کہ مہتمم یا ناظم جامعہ کی تصدیق شدہ ہوں، بھیجنا لازمی ہے۔‘‘
اس فیصلے کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں بندہ چند انتہائی مودبانہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے:
۱۔ تصاویر کی حرمت میں صرف بخاری شریف کے ایک باب میں دس احادیث موجود ہیں اور بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں جو احادیث آئی ہیں، وہ مزید برآں ہیں۔ اس لیے تصویر کشی اور تصویر کے استعمال کی حرمت پر پوری امت کے علماء حق متفق ہیں۔ آج سے ۹۶ سال پہلے یعنی ۱۳۳۶ھ میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوٹو گرافی کی شرعی حیثیت پر ایک مفصل مضمون لکھا جو ماہنامہ ’’المعارف‘‘ اعظم گڑھ میں کئی قسطوں میں شائع ہوا جس میں انھوں نے فوٹو کے جواز کا عندیہ ظاہر کیا تھا۔ چونکہ یہ مسلک صریح احادیث کے خلاف تھا، اس لیے اس کی تردید میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا اور اسے ماہنامہ ’’القاسم‘‘ دار العلوم دیوبند میں شائع کرایا۔ بعد میں وہ مقالہ کتابی شکل میں ’’تصویر کے شرعی احکام‘‘ کے نام سے چھپا جس میں مفتی صاحب نے مولانا ندوی صاحب کے شکوک وشبہات کا ازالہ کیا ہے اور یہ بات قوی دلائل سے ثابت کی ہے کہ شریعت محمدیہ میں تصویر بنانا، بنوانا اور استعمال کرنا سب حرام ہے۔ یہ مقالہ پڑھنے کے بعد مولانا ندوی صاحب نے بھی اپنے مسلک سے رجوع کر لیا تھا۔
۲۔ نقل ومتبادل کا سدباب واقعی ضروری ہے مگر جائز طریقوں سے، ناجائز سے نہیں۔ تصویر کی حرمت منصوص ہے اور نقل کرنا اورمتبادل بٹھانا احتمالی معاملہ ہے، تو ایک احتمالی عمل کی روک تھام کے لیے منصوص حرام کو کس طرح حلال کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نقل ومتبادل کی روک تھام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر وفاق المدارس العربیہ کے منتظمین حتی الوسع جائز تدابیر کریں، پھر بھی چند افراد یہ ناجائز کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا وفاق المدارس کے منتظمین گناہ گار ہوں گے؟ میرے ناقص علم کے مطابق وہ بالکل ماخوذ عند اللہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے۔
۳۔ طلبہ کے لیے امتحان کے دوران تصویر لازم ہونے سے صرف متبادل امیدوار کو روکنے میں کامیابی کا امکان ہے، اس سے نقل کی روک تھام نہیں ہو سکتی، حالانکہ نقل کا رجحان بھی متبادل سے زیادہ ہے اور اس کا نقصان بھی۔ جب فوٹو لازم کرنے سے نقل کا رجحان ختم نہیں ہوتا تو پھر اتنا عظیم گناہ کروانے سے کیا فائدہ؟ پھر یہ کہ اس طریقے سے متبادل کی روک تھام بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کسی نے دھوکہ دہی کا تہیہ کر رکھا ہو تو اس کا راستہ بند کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر ایک راستہ بند کیا جائے گا تو وہ دوسرا راستہ نکال لے گا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی صورت حال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں بہت پہلے سے تصاویر لازم ہیں، مگر جس پیمانے پر وہاں نقل اور متبادل کا طریقہ عام ہے، وفاق المدارس کے امتحان میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا۔ اگر دل میں تقویٰ اور خوف خدا نہ رہے تو جعل سازی کے لیے بے شمار طریقے نکالے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ نقل کرنے اور متبادل بٹھانے والے زیادہ سے زیادہ سو میں پانچ ہوں گے۔ باقی پچانوے طلبہ جن کا دامن اس فعل شنیع سے پاک ہے، ان سے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کس جرم میں کروایا جائے گا؟
۴۔ وفاق المدارس کی تنظیم یوم تاسیس سے لے کر آج تک سارے ادوار میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث، متقی اورمتبحر علماء کرام کی سرپرستی میں رہی ہے، اس لیے اس ادارے نے نہ صرف مدارس ومساجد کا تحفظ کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی تحفظ کیا ہے۔ اس بنا پر عام مسلمان اس ادارے کے ہر فیصلے کو حجت شرعیہ سمجھتے ہیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وفاق نے دوران امتحان مدارس کے طلبہ کے لیے تصویر کو لازم قرار دیا ہے تو ان کا یہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ چودہ سو تیس سال تک علما ہمیں یہ بتاتے رہے کہ فوٹو کھینچنا اور استعمال کرنا منع ہے، اب انھوں نے اپنے لیے اسے جائز کر لیا ہے۔ دین سے بے زار لوگ اس فیصلے کو عوام میں اس طرح اچھالیں گے کہ حرام صرف عوام کے لیے ہے، علما کے لیے کوئی چیز حرام نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس فیصلے کے بعد بے دین لوگ ہر قسم کے فوٹو کو ہر وقت جائز سمجھیں گے اور دلیل یہ پیش کریں گے کہ پھر طلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیوں جائز ہے؟
۵۔ وفاق المدارس کے زیر انتظام جیسے بنین کے امتحانات لیے جاتے ہیں، اسی طرح بنات کے امتحانات بھی لیے جاتے ہیں۔ جس بات کو فوٹو کے جواز کے لیے سبب بتایا گیا ہے، وہ بنات کے امتحانات میں بھی موجود ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان کے لیے بھی تصاویر کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ خدانخواستہ اگر وفاق المدارس نے امتحان کے دوران بنات کے لیے بھی تصاویر کو لازم قرار دیا تو اس دن یہود ونصاریٰ کی این جی اوز جو مسلمانوں میں بے حیائی وفحاشی پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، خوشی سے مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہوں گی۔
۶۔ وفاق المدارس کے امتحانات اکثر مساجد کے اندر لیے جاتے ہیں اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر اورفرشتوں کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مکان میں تصویر ہو، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب مسجد میں سیکڑوں ہزاروں تصویریں جائیں گی تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بدبودار چیز (پیاز یا لہسن) کھائے تو جب تک اس کے منہ سے بدبو زائل نہ ہو جائے، مسجد میں نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے اذیت ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جس امتحان کے دوران فرشتے وہاں نہیں آ سکیں گے، اس علم میں کتنی برکت ہوگی؟
۷۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر کی تفسیر آپ حضرات سے ہی یہ سنی ہے کہ مال کو ناجائز کام پر خرچ کیا جائے تو یہ تبذیر ہے اور اگر جائز مصرف پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو اسراف ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک طالب علم کے تین تصاویر بنانے پر کم از کم چالیس روپے خرچ ہوں گے اور وفاق المدارس کے امتحان میں ایک لاکھ سے زائد طلبہ امتحان میں شریک ہوتے ہیں۔ یوں ایک سال کے امتحان میں چالیس لاکھ روپے تصاویر پر خرچ ہوں گے۔ اتنی خطیر رقم شاید تین چار متوسط مدارس کے سالانہ اخراجات کے لیے کافی ہوگی۔ غور کی بات ہے کہ صرف ایک سال میں چالیس لاکھ روپے فی سبیل الشیطان لگانا اور ایک لاکھ طلبہ کو شیطان کے بھائی بنانا یہ دن کی کون سی خدمت ہے؟
۸۔ ممکن ہے آئندہ سالوں میں یہ فیصلہ بھی صادر کر دیا جائے کہ کوئی طالب علم امتحان گاہ میں پگڑی، قمیص اور شلوار کے ساتھ نہ آئے، بلکہ ننگے سر اور کوٹ پتلون پہن کر آئے کیونکہ پگڑی، قمیص اور شلوار میں نقل کا مواد چھپائے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ مظلوم طلبہ مجبوراً اس فیصلے کی بھی تعمیل کریں گے۔
۹۔ امتحان کے لیے تصویر بنوانے کو کرنسی، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں دو قسم کے لوگوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اصحاب اقتدار کے لیے کرنسی میں فوٹو چھاپنا اور شناختی کارڈ وپاسپورٹ میں تصویر کو لازم قرار دینا حرام ہے کیونکہ یہ ان کے اختیار میں ہے کہ ان چیزوں سے فوٹو کو ختم کر دیں، مگر رعایا کے لیے ان چیزوں میں تصویر لگانا اور ان چیزوں کو گھر میں اور جیبوں میں رکھنا جائز ہے، کیونکہ وہ بے چارے مجبور ہیں۔ چونکہ ہمارے حکمران یہود ونصاریٰ کے غلام ہیں، وہ شرعی احکام کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ صرف امریکہ وبرطانیہ کے اشاروں پر چلتے ہیں، اس لیے وہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مگر آپ حضرات تو امت مسلمہ کے مقتدا ہیں، پوری امت کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ حضرات کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی معمولی سی غلطی سے پوری امت غلطی میں پڑ جائے گی۔ ہمیں یہ وہم وگمان بھی نہ تھاکہ آپ حضرات صریح نصوص کے خلاف فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ اصحاب اقتدار سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ کرنسی اور شناخی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ سے تصویر کو ختم کریں، مگر صد افسوس کہ آپ نے خود تصویر کو لازم قرار دے دیا۔
چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی
ایک حدیث میں آیا ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ سیءۃ فعمل بہا بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بہا (مسلم ج ۲ ص ۳۴۱) اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کا فیصلہ اس حدیث کا مصداق بن جائے۔
۱۰۔ تقریباً پچاس سال سے وفاق المدارس کے زیر اہتمام سالانہ امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ اس پورے عرصے میں ہمارے اکابر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، حضرت مولانا محمد ادریس، حضرت مولانا عبد الحق، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہم اللہ نے ضرورت کے باوجود تصویر کو لازم کرنا تو دور کی بات، اس کی اجازت تک نہیں دی۔ آج بھی ان حضرات پر اعتماد کر کے ان کی پیروی انتہائی ضروری ہے۔
ان سب وجوہ کی بنا پر آپ حضرات سے انتہائی مودبانہ عرض اور التجا ہے کہ خدا کے لیے اس فیصلے کو واپس لیجیے۔ یہ آپ کا علما، طلبہ، عوام الناس اور پوری امت پر بڑا احسان ہوگا اور ہم قیامت تک آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔
اگر اس خط میں نادانستہ ایسے الفاظ درج ہو گئے ہوں جن سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس پر ہزار دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ واللہ، میرے دل میں آپ حضرات کے ساتھ عقیدت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ خط خالصتاً خیر خواہی کی بنا پر لکھا ہے۔
سخی داد خوستی، ژوب
طب مشرق کا جادو
حکیم محمد عمران مغل
طب کا ایک معنی جادو بھی ہے۔ یہ جادو جالینوس ثانی حکیم محمد حسن قرشیؒ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے معالجین اور مفکرین کے سامنے نہ صرف جگایا بلکہ حاضرین مجلس کو انگشت بدنداں بھی کر دیا۔
جاویدمنزل گڑھی شاہو لاہورکے وسیع دالان میں برصغیر کے مایہ نازمعالجین کرام کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ درد گردہ کی شدت سے ماہی بے آب کی طرح بے تاب ہیں۔ علاج کی ہر امکانی کوشش کے باوجود درد ختم نہیں ہو رہا۔ چار وناچار علامہ مرحوم کی خدمت میں گزارش کی گئی کہ طب مغرب کا ساز تو سنا جا چکا ہے، بہتر ہے کہ طب مشرق کی آواز بھی سنی جائے۔ علامہ مرحوم حکیم نابینا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کئی بار مسحور کن ادویہ کھا چکے تھے، چنانچہ خادم کو علامہ محمد حسن قرشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا گیا جس نے اب تک کی تمام کیفیت گوش گزار کی۔ حکیم صاحب دوا کے ساتھ شاعر مشرق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
حاضرین مجلس نے دیکھا کہ مرج البحرین میں ایک جوش اٹھا جس سے ایک در نایاب (دوا کی گولی) کنارے پر آن لگا۔ قرشی صاحب نے علامہ مرحوم کو گولی دی کہ اسے نیم گرم قہوہ کے ساتھ نگل لیں۔ چند لمحوں بعد علامہ مرحوم ایک انجانی چستی کے ساتھ بستر علالت سے اٹھ بیٹھے۔ ساتھ ہی فرمانے لگے کہ درد بالکل ختم ہو گیا ہے۔ حاضرین نے دیکھاکہ شاعر مشرق کا نہ صرف درد کافور ہوا، بلکہ بے چینی دور اور چہرہ مسرور ہو گیا۔
اپریل ۲۰۱۱ء
پاک بھارت تعلقات: ایک جائزہ (یوگندر سکند کے سوالنامہ کے جوابات)
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
سوال نمبر ۱۔ بھارت اور پاکستان دونوں اپنے قومی تشخص کی بنیاد ایک دوسرے کی مخالفت کو قرار دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایسی صورت حال میں دونوں ملکوں کے مابین پرامن تعلقات حقیقتاً ممکن ہیں؟
جواب: قیامِ پاکستان کے وقت پاکستان کے قومی تشخص کی بنیاد یہ تھی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور اپنے دین کے حوالے سے الگ تشخص رکھتے ہیں، اس لیے جس خطے میں ان کی اکثریت ہے، وہاں ان کی الگ ریاست قائم ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ایسٹ تیمور میں مسیحی اکثریت وہاں الگ ریاست کا باعث بنی اور اب جنوبی سوڈان اسی مسیحی اکثریت کے حوالے سے الگ ملک بننے جا رہا ہے۔ مگر قیام پاکستان کے بعد ہماری رولنگ کلاس جس کی تربیت نوآبادیاتی ماحول میں ہوئی تھی اور وہ وہی نفسیات ومزاج رکھتی تھی، دین کی بنیاد پر تشخص اور قومی بنیاد اسے ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی برصغیر کی تقسیم کے ایجنڈے کو مسئلہ کشمیر کھڑا کر کے الجھا دیا گیا، اس لیے باہمی دشمنی کی بنیاد پر قومی تشخص کی روایت آگے بڑھتی گئی۔ میرے نزدیک یہ مصنوعی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنی اصل بنیاد کی طرف واپس لوٹ جائیں اور بھارت بھی اس کا عملی احترام کرے تو اس دشمنی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر سعودی عرب اورایران کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات ومعاملات ہو سکتے ہیں تو ایک اسلامی پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟
سوال نمبر۲۔ بھارت اور پاکستان دونوں میں انتہا پسند عناصر موجود ہیں (پاکستان میں اسلامی اور بھارت میں ہندو) جو دونوں ممالک کے مابین پرامن اور بہتر تعلقات کے شدت سے مخالف ہیں۔ اس مشکل پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اسلامی زاویہ نگاہ سے آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جواب: میرے خیال میں یہ بات شاید قرین قیاس نہیں ہے کہ پاکستان میں جن طبقات کو انتہا پسند اور شد ت پسند سمجھا جاتا ہے، وہ بھارت کے ساتھ دشمنی کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کافراکثریت کا ملک ہے۔ اگر ایسا ہوتو ان کے جذبات چین کے با رے میں اسی طرح کے ہونے چاہییں، اس لیے پاکستان کے انتہا پسند طبقوں کی شدت پسندی کے اسباب کچھ اور تلاش کرنے چاہییں۔ غالباً مسئلہ کشمیر کے حل میں مسلسل تاخیر اور مشرقی پاکستان کی بنگلہ دیش کی صورت میں پاکستان سے علیحدگی میں بھارت کا کردار ان شدت پسندانہ جذبات کی اصل وجہ ہے اور اس مبینہ شدت پسندی کو کم کرنے کی کوئی بھی کوشش اس کے پس منظر کا لحاظ رکھے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔
سوال نمبر۳: پاکستان کے انتہا پسند گروپ مثلاً لشکر طیبہ کا اصرار ہے کہ بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات ممکن نہیں اور یہ کہ مسلمانوں کو ہر حال میں بھارت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا تا آنکہ وہ ایک عظیم تر پاکستان میں ضم ہو جائے۔ اس موقف کے با رے میں آپ کے احساسات کیا ہیں؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟
جواب :یہ جذبات دونوں طرف یکساں طور پر پائے جاتے ہیں۔ بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کا نعرہ اکھنڈ بھارت کا ہے اور پاکستان کے انتہا پسند مسلمان دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم لہرانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دونوں جذباتی باتیں ہیں۔ جب تک باہمی تنازعات کے حل کی کوئی صورت نہیں نکلتی، یہ نعرے اسی طرح لگتے رہیں گے۔ اس کا راستہ تلاش کرنا دونوں طرف کے سنجیدہ راہ نماؤں کی ذمہ داری ہے۔
سوال نمبر۴: پاکستان کے انتہا پسند اسلامی گروپ مثلاً لشکر طیبہ کتب حدیث میں موجود ایک روایت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں غزوۃ الہند کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس غزوے میں شریک ہوں گے، وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ آپ کی رائے میں اس حدیث کا کیا درجہ ہے؟ کیا یہ صحیح اور متواتر ہے؟کیا آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر طیبہ جیسے گروہ اس سے مراد موجودہ حالات میں انڈیا کے خلاف جہاد کرنا لیتے ہیں اور کیا اس حدیث کی یہ تعبیر درست ہے؟
جواب:غزوہ ہند کی روایات موجود ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پیش گوئیاں عالمی صورتحال میں پوری ہو چکی ہیں او ر باقی بھی اپنے وقت پر پوری ہوں گی، لیکن ان کا وقت متعین نہیں ہے اور ان کی کسی بھی موقع پر تطبیق کرنا ایسا کرنے والوں کے اپنے ذوق، استنباط اور استدلال کے درجہ کی باتیں ہیں۔ ماضی میں بھی اس خطے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی بہت سی جنگوں پران کا اطلاق کیا گیا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ لیکن کیا قوموں اور ملکوں کی پالیسیوں اور تعلقات کی بنیاد ان پیش گوئیوں پر رکھی جا سکتی ہے؟ یہ بات محل نظر ہے۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ ان پیش گوئیوں میں کوئی وقت طے نہیں کیا گیا، اس لیے قوموں اور ملکوں کی پالیسیوں میں ان کو بنیاد بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ پیش گوئیاں پوری ہونا الگ بات ہے اور کسی پیش گوئی کو از خود پورا کرنے کا عمل اس سے مختلف امر ہے۔ آج کے دور میں کسی مسلمان ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی بنیاد معروضی حالات، دو طرفہ مفادات اور مسلمہ بین الاقوامی عرف وتعامل ہی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔
سوال نمبر۵۔ آپ کی سیاسی جماعت، جمعیت علمائے اسلام کا پاک بھارت تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے علانیہ موقف کیا ہے؟
جواب: میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ایک غیر متحرک رکن ہوں اور اس کی پالیسی سازی اور قیادت میں میرا ایک عرصہ سے کوئی کردار نہیں ہے جب کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمن ہیں جو پاکستانی پارلیمنٹ کی قومی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے بہتر تعلقات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے۔ وہ اگر بین الاقوامی معاہدات واعلانات اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہو جائے تو باقی تنازعات ومعاملات میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔
سوال نمبر ۶۔ آپ کے خیال میں مسلم اور ہندو مذہبی قائدین دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کیا اب تک فروغ امن کی کوششوں کے حوالے سے ان قائدین کی غیر فعالیت یا خاموشی کے ان تعلقات پر کوئی منفی یا مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں؟
جواب:مسلم اور ہندو مذہبی قائدین کے درمیان ملاقاتوں اور مکالمہ کی کوئی صورت نکل سکے تو اس سے فائد ہ ہوگا، لیکن یہ مکالمہ باہمی مشترکات کے فروغ، شدت پسندی کو کنٹرول کرنے اور خطے کے امن اور ترقی کے حوالے سے ہو۔ میر ا خیال ہے کہ مذہبی راہ نما اگر خلوص کے ساتھ مل بیٹھیں تو وہ زیادہ بہتر تجاویز دے سکتے ہیں۔
سوال نمبر۷۔ جمعیت علماے ہند نے حال ہی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑا کنونشن منعقد کیا ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جموں اورکشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں اور کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق یا خود مختاری کے خلاف ہیں (جب کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر میں بھارتی افواج کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت بھی کی ہے)۔ ایک پاکستانی، ایک عالم اور ایک دیوبندی جماعت کے رکن کی حیثیت سے آپ اس موقف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جواب:میرا خیال ہے کہ اس مسئلہ کو قومی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ کسی بھی ملک کی کسی کمیونٹی کے لیے قومی مسائل میں قومی موقف سے انحراف مناسب نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے پاکستان میں رہنے والی اقلیت کشمیر سمیت تمام قومی مسائل میں قومی موقف کی تائید کرتی ہے اور کم وبیش ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔
سوال نمبر۸: آپ کے خیا ل میں مسئلہ کشمیر کے حل کا بہترین، معقول ترین اور عملی حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟
جواب: مسئلہ کشمیر کے حل کی دو ہی اصولی بنیاد یں ہیں: مسلمہ بین الاقوامی معاہدات اور کشمیری عوام کی آزادانہ مرضی۔ اس سے ہٹ کر کوئی حل شاید ہی کامیاب ہو سکے۔ اگر اقوام متحدہ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان میں استصواب رائے کر اسکتی ہے تو کشمیر میں استصواب رائے کروانے میں اسے ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے اور میرے خیال میں یہی اسی مسئلے کا صحیح حل ہے۔
سوال نمبر ۹: پاکستان کے انتہا پسند اسلامی گروہ بھارت اور ہندوؤں کی شدید مخالفت پر مبنی آئیڈیالوجی کا پرچار کرتے اور اسلام کی تعبیر بھی اس کے مطابق کرتے ہیں۔ (اسی طرح ہندو انتہا پسند گروپ بھی بھارت میں پاکستان اور اسلام کی شدید مخالفت پر مبنی آئیڈیالوجی کا پرچار کرتے ہیں۔) آپ کی رائے میں اس انتہا پسندانہ اسلامی موقف کے منفی اثرات ہندوؤں کو دعوت اسلام دینے کی ذمہ داری پر کیا پڑتے ہیں جن میں بھارت کے ہندو بھی شامل ہیں اور پاکستان کی ہندو اقلیت بھی؟
جواب: میرے خیال میں دونوں طرف صورت حال ایک جیسی ہے۔ مسلمانوں کے ایک بڑے حصے میں بھارت اور ہندوؤں کے خلاف شدید مخالفت پائی جاتی ہے اور ہندوؤں کے ایک بڑے حلقے میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اسی درجہ کی شدید مخالفت کا رویہ بھی موجود ومتحرک ہے۔ اسی طرح دعوت کے میدان میں ہندوؤں کو مسلمان کرنے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے اور ہندوستان کے بہت سے مسلمانوں کو ہندو مذہب سے منحرف قرار دے کر واپس ہندو مذہب میں شامل کرنے کی تحریک بھی کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں دونوں طرف کے اعتدال پسند راہ نماؤں کو کردار ادا کرنا چاہیے جس کا دائرہ باہمی گفتگو اورمشترکہ جذبہ کے ساتھ ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ منافرت، دشمنی اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کا ماحول دونوں طرف سے دعوت کے عمل میں رکاوٹ ہے۔ اس کا دونوں طرف کے سنجیدہ راہ نماؤں کو جائزہ لینا چاہیے۔
سوال نمبر۱۰:بھارت اور ہندو مخالف جذبات کے، جنھیں دوسرے عوامل کے علاوہ نام نہاد اسلامی عناصر بھی بھڑکاتے ہیں، پاکستان کی ترقی پر مثبت یا منفی اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں؟ کیااس کو فرقہ وارانہ، طبقاتی اور علاقائی تقسیم کے تناظر میں پاکستانی قوم میں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اس رویے کے حامیوں نے کوشش کی ہے؟ کیا یہ پاکستانی قوم یامسلمانوں میں وحدت پیدا کرنے کا ایک فی الواقع اسلامی منہج ہے؟
جواب: میرے خیال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان قومی سطح پر دشمنی کے جذبات کا ماحول برقرار رکھنا عالمی استعمار کی طے شدہ پالیسی اور ایجنڈے کا حصہ ہے جو دونوں ملکوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور شاید عالمی ایجنڈے کا بنیادی ہدف بھی یہی ہے۔ سوال نمبر ۱ کے جواب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ ماحول مصنوعی ہے۔ پاکستان میں قوم کی وحدت کی اصل بنیاد بھارت دشمنی نہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت وعقیدت ہماری قومی وحدت کی اصل اساس ہے جس کا اظہار ابھی حال میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے حوالے سے قوم کے کم وبیش تمام طبقات نے متحد ہو کر ایک بار پھر کر دیا ہے۔
سوال نمبر ۱۱۔پاکستان کے اسلامی گروپوں کی طرف سے بھارت اور ہندو مخالف جذبات کو ہوا دینے کی پالیسی کے مضمرات بھارت کی مشکلات کا شکار مسلم اقلیت کے حوالے سے کیا ہیں؟ کیا پاکستانی گروہوں نے اس بات پر کبھی غو ر کیا ہے کہ ان کے بھارت مخالف رویے کے یقینی طور پر منفی اثرات بھارتی مسلمانوں کی زندگیوں، تحفظ اور بھلائی پر پڑیں گے اور اس سے بھارت کے انتہا پسند ہندو گروپوں کو تقویت ملے گی؟
جواب: یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کی طرف سے ہندؤں اور بھارت کے خلاف شدت پسندانہ جذبات کے اظہار کے اثرات بھارت کی مسلمان اقلیت پرپڑتے ہیں، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ بھارت میں اسلا م اور پاکستان کے خلاف شدت پسندانہ جذبات کے اظہار کے اثرات پاکستان میں بسنے والی ہندو اقلیت پر کیوں نہیں پڑتے؟ اگر اس پہلو سے تقابل کیا جائے تو دونوں طرف کی صورت حال ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ میرے خیال میں بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا بھارتی قومیت کے ساتھ مضبوط تعلق اور بھارت کے امن وترقی کے لیے ان کابھرپور کردار اس قدر مستحکم ہے کہ اس طرح کے اثرات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ یہ بات اصولی طور پر درست ہے کہ کسی بھی معاملے میں شدت پسندانہ رویہ بہرحال ٹھیک نہیں ہوتا۔ اعتدال اور توازن کا راستہ ہی ہر دور میں بہتر اور مفید رہا ہے اور دونوں طرف سے اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے۔
ریمنڈ ڈیوس کیس کے تناظر میں اسلامی فوجداری قانون کا ایک مطالعہ
پروفیسر میاں انعام الرحمن
اس وقت ہر طرف شور و غل برپا ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے پاکستانیوں کے ایک امریکی قاتل کو باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ بات سو فی صد غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک عدالت کے ایک ’قاضی‘ نے پاکستانی مسلمانوں کے ایک غیر مسلم امریکی قاتل کو ’دیت‘ لے کر چھوڑ دیا ہے۔ وطن عزیز کے اسلام پسندوں کو خوشی کے شادیانے بجانے چاہییں کہ امریکہ بہادر کم از کم ایک اسلامی قانون کی ’حکمتوں‘ کا قائل ہو گیا ہے اور یہی امر سیکولر لبرل حلقوں کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے کہ اسلامی قوانین کی حکمتیں اگر اسی انداز میں جلوہ افروز ہوتی رہیں تو وہ دن دور نہیں جب ان قوانین کو سامراجی ہتھکنڈے کے طور پر نافذ کرنے کے لیے عالمی استعماری طاقتوں کی مہربانیوں اور فنڈز کا رخ مکمل طور پر اسلام پسندوں کی طرف ہو جائے گا اور سیکولر لبرل این جی اوز حیرت و حسرت سے منہ تکتی رہ جائیں گی۔
قارئین کرام! ریمنڈ ڈیوس کیس میں قصاص و دیت کے جس جاں فزا اسلامی قانون کو ’برتا‘ گیا ہے، اس قانون کے مندرجات میں الجھے بغیر ہم کوشش ہو گی کہ قصاص و دیت کے قرآنی مفاہیم کے تناظر میں اس کیس کو سمجھنے کی سعی کریں۔ ہماری یہ کاوش سیکولر لبرل حلقوں کے لیے تو ناقابلِ قبول ہی ہوگی، لیکن توقع ہے کہ حدود اللہ اور حدود قوانین میں فرق نہ کرنے والے اسلام پسندوں کو بھی اس پر جذباتی اچھل کود کے اچھے خاصے مواقع میسر آئیں گے۔
قرآنی تناظر میں دیت اور ریاستی اختیار
اس وقت ریاستی موقف کے مطابق، ریمنڈ ڈیوس کیس میں ورثا نے دیت لے کر امریکی قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل کے کسی بھی کیس میں دیت کی صورت میں معاملہ طے کرانے میں کیا ریاست دخل اندازی کر سکتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ریاستی مداخلت کس نوعیت کی اور کس حد تک ہو سکتی ہے؟ رائج الوقت حدود قوانین سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اگر ہم نصوصِ قرآنی کی طرف براہ راست رجوع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ:
(۱)اصلاً ریاستی اختیار کی نوعیت، بنیادی طور پر دیت کی ’ادائیگی‘ کو یقینی بنانے تک محدود ہے اور یہ اختیار بھی تب عمل میں آتا ہے جب فریقین (قاتل اور مقتول کے ورثا معاشرتی مداخلت کے بعد) قصاص کے بجائے دیت پر باہم رضامند ہو جائیں۔
(۲) جہاں تک دیت کا معاملہ طے کرانے کا تعلق ہے، اس میں ریاست کی براہ راست مداخلت کسی نص شرعی سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ریاست کی زیادہ سے زیادہ مداخلت، صرف پس منظر میں رہتے ہوئے (بالواسطہ طور پر ایسی عمومی) سماجی فضا انگیخت کرنے تک محدود ہے جس کی موجودگی، قتل کے اکثر کیسوں میں مقتول کے ورثا کو قصاص کے بجائے دیت لینے پر بغیر جبر و اکراہ کے آمادہ کرسکتی ہے۔ اس نکتے کے مطابق اگرچہ معاملہ طے کرانے میں ریاستی مداخلت کی گنجائش نکل آتی ہے لیکن اس گنجائش پر بھی دو قدغنیں عائد ہوتی ہیں:
(۱) ریاست دیت کا معاملہ طے کرانے میں براہ راست دخیل نہیں ہو سکتی، بلکہ بالواسطہ انداز میں ہی معاشرے کی (خوابیدہ)عمومی اخلاقی حِس کو بیدار کرنے کی کوشش کر سکتی ہے تاکہ اس اخلاقی قوت کے بل بوتے پر سوسائٹی میں قصاص کے بجائے عفو و احسان (فَمَنْ عُفِیَ لَہُ مِنْ أَخِیْہِ شَیْْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْْہِ بِإِحْسَان) جیسی اقدار پھل پھول سکیں۔ اس سلسلے میں براہ راست مداخلت کا اصلاً اور بالفعل اختیار صرف اور صرف معاشرے (بشمول قاتل و مقتول کے ورثا)کا ہی ہے۔
(۲) پھر یہ بالواسطہ ریاستی مداخلت بھی کسی ’مخصوص کیس‘ کے لیے بطورِ خاص کسی خاص وقت پر نہیں کی جا سکتی کہ اس عمل سے معاشرے کو ’ہائی جیک‘ کرنے کا تاثر پھیلے گا نہ کہ دیت کی عمومی ترویج کے لیے ریاستی فرائض کی ادائیگی کا بھر پور احساس تاثر پکڑے گا۔
مذکورہ نکات نصوصِ قرآنی سے مستنبط ہیں۔ یہ ہماری ذہنی اختراع نہیں ہیں۔ اگرچہ روایتی فقہی مباحث میں دیت کے ضمن میں ریاستی اور معاشرتی حدود کی تفریق اس طرح غالباً نہیں کی گئی، لیکن یہ امر تقریباً طے شدہ ہے کہ قصاص و دیت اور معافی کے احکام کی بنیادی آیت سورۃ البقرۃ۲ کی آیت۱۷۸ جیسا سخت استوار حکم ہے۔
یَا أَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْْکُمُ الْقِصَاصُ فِیْ الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَی بِالأُنثَی فَمَنْ عُفِیَ لَہُ مِنْ أَخِیْہِ شَیْْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْْہِ بِإِحْسَانٍ ذَلِک تَخْفِیْفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۃٌ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِکَ فَلَہُ عَذَابٌ أَلِیْمٌ
اس میں (الْقِصَاصُ فِیْ الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَی بِالأُنثَی) جیسا سخت استوار حکم، جس کا مخاطب (یَا أَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْْکُمُ)مومنین کا مقتدر نظمِ اجتماعی( معروف معنوں میں ریاست) ہے، کے بعد (فَمَنْ عُفِیَ لَہُ مِنْ أَخِیْہِ شَیْْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْْہِ بِإِحْسَان) جیسے نرمی و لچک پر مبنی بیان، جس کا باقاعدہ اظہار (ذَلِک تَخْفِیْفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۃٌ)کے الفاظ میں کیا گیا ہے، اپنے اندر ایک دعوتِ فکر رکھتا ہے اور کئی سوالات کو جنم دیتا ہے مثلاً:
(۱) شارع کا منشا اگرسختی (قصاص) ہی ہے تو پھر نرمی (دیت و معافی)کی گنجائش کیوں رکھی گئی ہے؟
(۲) اگر دیت و معافی ہی شارع کا منشا و مقصود ہے تو پھر قصاص کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟
(۳) قصاص کے حکم میں (کُتِب) کا لفظ لزومیت لیے ہوئے مومنین کے مقتدر نظمِ اجتماعی(ریاست) کو خطاب کرتا نظر آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟
(۴) عفو و احسان کے مخاطبین افرادِ معاشرہ ہیں نہ کہ مومنین کا مقتدر نظمِ اجتماعی، ایسا کیوں ہے؟
(۵) نکات ۳ اور ۴ کے مطابق مخاطبین بالترتیب ریاست اور معاشرہ ہیں، مخاطبین کا یہ فرق کیا حکمت لیے ہوئے ہے؟
(۶) آیت ۱۷۸ میں دیت و معافی کو مقصود کی سطح پر رکھتے ہوئے اس سے متصل آیت ۱۷۹ میں (فِیْ الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ) ’قصاص میں حیات ہے جیسے اٹھتے ہوئے اسلوب میں دوبارہ قصاص کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔
ہم نے اپنے مضمون ’’قرآن مجید میں قصاص کے احکام‘‘ میں اس قسم کے سوالات سے تعرض کیا ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ یہ سوالات داخلی شواہد پر مبنی جوابات لیے ہوئے اس آیت مبارکہ سے خود بخود ہمارے سامنے آئے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ماہنامہ الشریعہ ستمبر ۲۰۰۸ دیکھیے۔) اس مضمون کے ملخص کے مطابق دیت کا معاملہ طے کرنے اور طے کرانے میں قاتل و مقتول کے ورثا اور سماج کا کردار کلیدی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری قصاص کے اصول کو قائم رکھنے کی ہے تاکہ مقصود کی سطح پر دیت و معافی کے ضمن میں دھونس زبردستی نہ ہوسکے۔ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے سے (اس کیس کے صحیح یا درست ہونے سے قطع نظر )ایک اصولی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم نے مذکورہ مضمون میں بات نہیں کی تھی کہ اگر قاتل کوئی غیر ملکی ہو تو دیت طے کرنے کرانے میں اس کی اور اس کے متعلقین کی رسائی مسلم سوسائٹی تک کیسے ہو گی؟کیونکہ اس سلسلے میں ریاست اصولاً (نص کے مطابق) براہ راست مداخلت کی مجاز نہیں ہے۔ اندریں صورت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی غیر ملکی قاتل اور اس کے متعلقین کو مسلم ریاست سے بالا بالا مقتول کے ورثا اور سول سوسائٹی سے روابط قائم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟اور پھر وہ غیر ملکی ہو بھی غیر مسلم ، اور کسی ایسی قوم کا فرد ہو جو مسلم ریاست کے لیے کئی حوالوں سے کافی اہمیت رکھتی ہو۔ اس قسم کے سوالات فقہا کی توجہ کے مستحق ہیں۔ ہماری ناقص رائے میں مسلم ریاست کسی غیر ملکی قاتل کو (شاید) دیت کی آپشن دینے کی ہی پابند نہیں ہے، دیت کا معاملہ طے کرنا کرانا تو اگلی بات ہے۔ اس سلسلے میں ریاست اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی قصاص کے نفاذ کو ہی یقینی بنائے گی کیونکہ اس کی عمل داری (jurisdiction) میں اس سے رجوع کرنے کے بجائے کسی غیر ملکی نے اپنے طور پر معاملہ نمٹاتے ہوئے اسے کھلے عام دعوتِ مبارزت دی ہے۔ لیکن اس موقف کے لیے براہ راست استدلال سورۃ البقرۃ۲ آیت۱۷۸ سے(شاید) نہیں کیا جا سکتا (کیونکہ یہ بنیادی طور پر معافی کی آیت ہے)اس لیے اس سلسلے میں دیگر قرآنی آیات کا مطالعہ ناگزیر اور مفید ہوگا۔
قصاص اور جزاکے قرآنی مفاہیم
ہماری رائے میں امریکی قاتل ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں سورۃ البقرۃ۲ آیت ۱۷۸ جیسے قرآنی حکم کا اطلاق نہیں ہوتا (کیونکہ اس آیت کے مفاہیم میں قاتل کے قتل کرنے کے پیچھے موجود کسی نہ کسی ’جواز‘ کا لحاظ رکھا گیا ہے)۔ اگر نرمی کو بہت ہی غالب رکھا جائے تو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ سورۃ بنی اسرائیل۱۷ آیت۳۳ (وَلا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّہُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّہِ سُلْطَاناً فَلاَ یُسْرِف فِّیْ الْقَتْلِ إِنَّہُ کَانَ مَنْصُوراً) جیسے قرآنی حکم کے مطابق نمٹانا جانا چاہیے تھا جس کے مطابق مظلوم مقتول کے ولی کو ’سلطان‘ قرار دیتے ہوئے معاشرتی و ریاستی طاقت اس کی پشت پر کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ وہ(ولی) قصاص لازماًلے سکے لیکن اسراف کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ (تفصیلی بحث کے لیے ماہنامہ الشریعہ اکتوبر۲۰۰۸ میں ہمارا مضمون ’قرآن مجید میں قصاص کے احکام قسط ۲‘ ملاحظہ کیجیے)۔
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی قاتل ریمنڈ ڈیوس قصاص کا نہیں بلکہ جزا کا مستحق تھا۔ سورۃ النساء۴ آیت۹۳ (وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُہُ جَہَنَّمُ خَالِداً فِیْہَا وَغَضِبَ اللّہُ عَلَیْْہِ وَلَعَنَہُ وَأَعَدَّ لَہُ عَذَاباً عَظِیْماً) سے معلوم ہوتا ہے کہ (فَجَزَآؤُہُ) یک طرفہ کارروائی ہے۔ اس میں نہ تو قاتل کے لیے کسی قسم کی گنجائش (قانونی، اخلاقی، سماجی وغیرہ) نظر آتی ہے اور نہ ہی کسی بھی درجے میں مقتول مومن کے ورثا کو قابلِ توجہ سمجھا گیا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ’طے‘ کر دیا گیا ہے کہ مومن کو عمداً قتل کرنے والے قاتل کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے اور وہ ہے (جَہَنَّمُ خَالِداً فِیْہَا وَغَضِبَ اللّہُ عَلَیْْہِ وَلَعَنَہُ وَأَعَدَّ لَہُ عَذَاباً عَظِیْماً)۔ لیکن اس قرآنی حکم کے سرسری جائزے سے یہ مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ (فَجَزَآؤُہُ) اور اس کے بعد (جَہَنَّمُ خَالِداً فِیْہَا وَغَضِبَ اللّہُ عَلَیْْہِ وَلَعَنَہُ وَأَعَدَّ لَہُ عَذَاباً عَظِیْماً)کا بیان صرف اور صرف اخروی سزا کے لیے آیا ہے، دنیاوی سزا سے اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت میں ’قصاص‘ کے لفظ کی عدم موجودگی دنیاوی سزا کے تعطل پر دلالت نہیں کرتی بلکہ قصاص کے متبادل کے طور پر لایا گیا لفظ ’جزا‘ قصاص سے بہت بڑھ کر سزا کی ایسی نوعیت کی غمازی کرتا ہے جس میں کیفیت میں عدم تطابق کے تدارک کے لیے اور وزن و کمیت میں برابری کی خاطر، سزا میں ظاہری طور پر مختلف صورت کا اپنایا جانابھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں ’جزا‘ کے اطلاقات ہمارے موقف کی تنقیح کرتے ہیں مثلاً:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَۃُ فَاقْطَعُواْ أَیْْدِیَہُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّہِ وَاللّہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ (المائدۃ۵ :۳۸)
’’ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو ، ان کے کیے کی جزا اللہ کی طرف سے عبرت ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے‘‘
اگر جزا کا مطلب(قصاص کے مانند) ویسا ہی بدلہ ہے توچور کی سزا چور کے ہاں چوری کی صورت میں ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ایسی ظاہری مطابقت ممکن نہیں تھی ، اس لیے عدم مطابقت کے تدارک کے لیے قطع ید کی جزا مقرر کی گئی۔پھر عام طور پر چور کا کٹا ہوا ہاتھ ، سماجی کلنک کی علامت بھی بن جاتا ہے جسے اللہ رب العزت نے (نَکَالاً مِّنَ اللّہِ) کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قطع ید اور (نَکَالاً مِّنَ اللّہِ) جرم کے عین مطابق سزا کے بجائے زیادہ سزا پر دلالت کرتے ہیں؟اس سلسلے میں ’جزا‘ کے دیگر قرآنی اطلاقات ، قطعیت کے ساتھ راہنمائی کرتے ہیں کہ سزا کی ایسی نوعیت سزا میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے ، لہذا اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے ’ ظلم‘ کی علامت بھی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں کسی منفی فعل یا جرم کا عین بدل ہے ، مثلاً:
مَن جَاء بِالْحَسَنَۃِ فَلَہُ عَشْرُ أَمْثَالِہَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَۃِ فَلاَ یُجْزَی إِلاَّ مِثْلَہَا وَہُمْ لاَ یُظْلَمُونَ (الانعام۶ :۱۶۰)
’’جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں اور جو برائی لائے تو اسے جزا نہ ملے گی مگر اس کے برابر ، اور ان پر ظلم نہ ہو گا‘‘
مَن جَاء بِالْحَسَنَۃِ فَلَہُ خَیْْرٌ مِّنْہَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَۃِ فَلَا یُجْزَی الَّذِیْنَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ إِلَّا مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ (القصص۲۸ :۸۴)
’’ جو نیک کام کرے اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا اور جو برا کام کرے تو انہیں جو برا کام انجام دیتے ہیں ، جزا نہیں ملے گی سوا اس کے جو وہ کرتے تھے‘‘
الْیَوْمَ تُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللَّہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ (غافر ۴۰:۱۷)
’’ آج ہر جان اپنے کیے کی جزا پائے گی آج کسی پر ظلم نہیں ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے‘‘
مَنْ عَمِلَ سَیِّئَۃً فَلَا یُجْزَی إِلَّا مِثْلَہَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَہُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّۃَ یُرْزَقُونَ فِیْہَا بِغَیْْرِ حِسَابٍ (غافر ۴۰ :۴۰)
’’ جو برا کام کرے اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اتنی ہی ، اور جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مومن ، پس وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں بے حساب رزق پائیں گے‘‘
وَخَلَقَ اللَّہُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ (الجاثےۃ ۴۵ :۲۲)
’’ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کی جزا پائے اور ان پر ظلم نہ ہو گا ‘‘
چور کو قطع ید کی جزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ، اگرچہ ظاہری طور پر زیادہ سزا معلوم ہوتے ہیں ، لیکن اگر قرآن مجید میں کسی کا مال حرام طریقے سے کھانے وغیرہ ، اور کسی سماج میں مال کی اہمیت وغیرہ ، کو مدِ نظر رکھا جائے تو قطع ید کی جزا، وزن و کمیت کے لحاظ سے جزا کی معنوی سطح پر پوری اترتی ہے اور جرم کا عین بدل معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے زیرِ نظر النساء۴ آیت ۹۳ کے مطابق بھی مقتول مومن کے قاتل کو قتل کرنا ہی جزا نہیں کہ ایسی جزا میں مقتول کے ’ایمان‘کا دھیان نہیں رکھا جاتا، اس لیے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ، جزا کی معنوی سطح کا اطلاق(بہ اعتبار وزن و کمیت ) اسی صورت ممکن ہے جب قاتل کے قتل سے بھی بڑھ کر سزا تجویز کی جائے ۔ شاید اسی لیے شارع نے اس آیت میں قصاص کے بجائے جزا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ المائدۃ آیت ۳۸ میں سے (نَکَالاً مِّنَ اللّہِ) اور النساء آیت ۹۳ میں سے (وَغَضِبَ اللّہُ عَلَیہِ) کا تنقیدی تقابلی مطالعہ شارع کے منشا کی مزید صراحت کرتاہے جس کے مطابق قرآنی مغضوبین کی ’ ذلت و محتاجی کی حالت‘ (نَکَالاً مِّنَ اللّٰہِ) سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ لہٰذا، زیرِ نظر النساء آیت ۹۳ میں ’جزا‘ کے مذکورہ مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، قرآنی مغضوبین کی ذلت و رسوائی پر بھی توجہ کی جائے ، تو استدلال کیا جا سکتا ہے کہ المائدۃ آیت ۳۸ کے مانند ، مومن کے قتل کی جزا کا وزن و کمیت کے لحاظ سے اطلاق ، قاتل کی ذلت و رسوائی کے بغیر ممکن نہیں ۔اہم بات یہ ہے کہ النساء آیت ۹۳ کے علاوہ ، قرآن مجید میں جن دو مقامات پر مغضوب و ملعون کااکٹھے ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی دنیاوی ذلت و رسوائی کا واضح اہتمام موجود ہے :
قُلْ ہَلْ أُنَبِّئُکُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِکَ مَثُوبَۃً عِندَ اللّہِ مَن لَّعَنَہُ اللّہُ وَغَضِبَ عَلَیْْہِ وَجَعَلَ مِنْہُمُ الْقِرَدَۃَ وَالْخَنَازِیْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِکَ شَرٌّ مَّکَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِیْلِ (المائدۃ ۵ :۶۰)
’’ تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ میں ہیں وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور طاغوت کے پجاری ، یہ لوگ جگہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھے راستے سے زیادہ ہٹے ہوئے ہیں ‘‘
وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکَاتِ الظَّانِّیْنَ بِاللَّہِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْْہِمْ دَائِرَۃُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّہُ عَلَیْْہِمْ وَلَعَنَہُمْ وَأَعَدَّ لَہُمْ جَہَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیْراً (الفتح ۴۸ :۶)
’’ اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اورمشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ،جو اللہ کی نسبت برے گمان رکھتے ہیں، ان پر برا وقت پڑنے والا ہے اور اللہ ان پر غضب ناک ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ‘‘
اس لیے یہ اخذ کرنا نص میں اضافہ نہیں ہو گا کہ النساء آیت۹۳ میں (فَجَزَآؤُہُ) کے بعد ، جہنم میں خلود ، اللہ کا غضب و لعنت اور عذابِ عظیم کی تیاری کابیان (کیفیت میں عدم تطابق کے تدارک اور وزن و کمیت میں برابری کی خاطر) مقتول مومن کے قاتل کے قتل سے بڑھ کر کسی ایسی مرکب سزا کی راہ دکھاتا ہے جس میں ذلت و رسوائی کا پہلو بدرجہ اتم موجود ہو ۔
سورۃ النساء۴ آیت۹۳ میں ’عمد‘ حق راہ جاننے کے حوالے سے تحقق اور اتمامِ حجت پر دلالت کرتا ہے اور پھر قرآن مجید نے تو مطلق انسان کے قتل کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے (المائدۃ۵:۳۲) چہ جائے کہ مومن کا عمداً قتل ہو۔ اگر اس نکتے کو بھی دھیان میں رکھا جائے کہ کہ تخلیقِ آدم سے قبل فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا قتل و غارت کرے گا ، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے مومن ، فرشتوں کے اس سوال کا جواب ہونے کے ناطے ایک جہت سے آیتِ الہی ہے اور دوسری جہت سے آیاتِ الہی کی تجسیم ہے ، نہ فسادی اور نہ قتل و غارت پر تلا ہوا ۔اس لیے اگر اس کا قتل ، آیتِ الہی کے خاتمے کی کوشش خیال کیا جائے تو اس کے قاتل کو ’جزا‘ کے طور پر لوگوں کے لیے آیت بنا دیا جانا چاہیے ،جیسا کہ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے:
وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا کَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاہُمْ وَجَعَلْنَاہُمْ لِلنَّاسِ آیَۃً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ عَذَاباً أَلِیْماً (۳۷)
’’اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ‘‘
اگرمومن کی دوسری جہت ، یعنی آیاتِ الہی کی تجسیم کو پیشِ نظر رکھا جائے تو:
وَالَّذِیْنَ سَعَوْا فِیْ آیَاتِنَا مُعٰجِزِیْنَ أُوْلَئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِیْمٌ (سبا ۳۴ :۵)
’’ اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی ، ان کے لیے سخت درد ناک عذاب ہے ‘‘
کے مصداق ، اس کا قتل ، آیاتِ الہی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اس لیے خدائی نظام میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش ہے اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے : وَالْفِتْنَۃُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرۃ ۲:۱۹۱) ’’اور فتنہ سخت تر ہے قتل سے‘‘ وَالْفِتْنَۃُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرۃ ۲ :۲۱۷) ’’اور فتنہ انگیزی ، قتل سے بھی بڑھ کر ہے‘‘۔ ایسے فتنہ و فساد پر قرآن نے خاموشی اختیار نہیں کی اور نہ ہی محض اخروی سزاؤں پر انحصار کیا ہے بلکہ ان کے سدِ باب کے لیے سخت دنیاوی تدابیر و سزائیں مقرر کی ہیں ، مثلاً: سورۃ النور آیت ۲ میں زانی مرد و عورت پر ترس نہ کھانے اور مومنین کے ایک گروہ کی حاضری کا حکم آیا ہے ، ظاہر ہے کہ اس حکم کے پیچھے جواز یہی ہے کہ زانی لوگ ، ایک لحاظ سے آیاتِ الہی کو چیلنج کرتے ہوئے ، قرآنی اقدار پر مبنی اجتماعی نظم میں خلل اندازی کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ ترس کے بجائے ذلت و رسوائی کے زیادہ مستحق ہیں ۔ زنا کے مقابلے میں مومن کا قتل ، آیاتِ الہی کو کلی اعتبار سے چیلنج کرنے کے مترادف اور اجتماعی نظم میں خلل اندازی کی انتہائی کوشش ہے ، اس لیے منطقی طور پر اس کے قاتل کے لیے نہ تو نرمی کا کو ئی گوشہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی ذلت و رسوائی میں کوئی کسر باقی چھوڑنی چاہیے۔ النساء۴ آیت ۹۳ کو دوبارہ دیکھیے (وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُہُ جَہَنَّمُ خَالِداً فِیْہَا وَغَضِبَ اللّہُ عَلَیْْہِ وَلَعَنَہُ وَأَعَدَّ لَہُ عَذَاباً عَظِیْماً)، اس میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا گیا جس میں قاتل کے لیے کسی حوالے سے نرمی کی ذرہ برابر بھی گنجایش نکلتی ہو ۔ اس کے برعکس ، سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۳ میں مقتول کے مظلوم ہونے کے باوجود (فَلاَ یُسْرِف فِّیْ الْقَتْلِ) کے الفاظ، ظالم قتل کے لیے ایک حد تک نرمی ظاہر کرتے ہیں ۔ اس لیے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ النساء آیت ۹۳ میں اس اسراف (سختی و رسوائی )کی اجازت(بلکہ حکم ) دیا گیا ہے جس کی بنی اسرائیل آیت ۳۳ میں ممانعت کی گئی ہے۔ اگرالمائدۃ آیت ۳۲ کے بیان (مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِیْ الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعاً وَمَنْ أَحْیَاہَا فَکَأنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیْعاً) ’’جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی ‘‘ میں انسانی جان کی حرمت اور قرآن میں مومن کے مقام پر نظر رکھتے ہوئے، النساء آیت ۹۳ میں قصاص کے مقابل ’جزا‘ کی معنویت کا احاطہ کرکے ، مذکور سزاؤں جہنم غضب لعنت عظیم عذاب پر غور و خوض کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے قاتل کے ساتھ ’اسراف‘ کرنے کی صورت میں بھی ’جزا‘ کا معنوی اطلاق (قاتل کے فعل کے مساوی ، وزن و کمیت کے لحاظ سے ) ممکن نہیں ہوتا ، اس لیے قاتل کی سزا کے لیے ایسے الفاظ (جہنم غضب لعنت عظیم عذاب) برتے گئے ہیں جو بدیہی طور پر اخروی سزا پر دلالت کرتے ہیں ، یعنی دنیاوی سزا کی کوئی بھی نوعیت چونکہ قاتل کے فعل کا بدل نہیں ہو سکتی ، اس لیے آخرت میں بھی اسے لازماََ سزا ملے گی ۔(آیت مذکور کے مزید پہلوؤں پر غور کے لیے ماہنامہ الشریعہ فروری۲۰۰۹ میں ہمارا مضمون’قرآن مجید میں قصاص کے احکام:قسط۳‘ ملاحظہ کیجیے)۔
عمداً قتل کیے جانے والے مومن کا ولی
سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۳ (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّہُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّہِ سُلْطَاناً فَلاَ یُسْرِف فِّیْ الْقَتْلِ إِنَّہُ کَانَ مَنْصُوراً) میں قاتل کو سزا دینے کے لیے مقتول کے ولی کی قانونی پوزیشن (ًفَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّہِ سُلْطَاناً) کے الفاظ میں واضح کی گئی ہے، لیکن النساء آیت ۹۳ میں مقتول مومن کے ولی کی قانونی پوزیشن کی تصریح کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ، بلکہ مزید غور سے دیکھا جائے تو ولی کا بیان ہی موجود نہیں، قانونی پوزیشن کی صراحت تو خیر اگلی بات ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اندازِ بیان سے شارع کا منشا کیا ہے؟ ( خیال رہے کہ البقرۃ آیت ۱۷۸ میں (فَمَنْ عُفِیَ لَہُ مِنْ أَخِیْہِ شَیْْءٌ) کے الفاظ اور المائدۃ آیت ۴۵ میں (فَمَن تَصَدَّقَ بِہِ فَہُوَ کَفَّارَۃٌ لَّہُ) کے الفاظ کسی فریق ثانی یا ولی کی موجودگی پر دلالت کر رہے ہیں ) جبکہ النساء آیت ۹۳ میں فریق ثانی وہ مومن ہے جس کو عمداََ قتل کیا جا چکا ہے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتول مومن کا قائم مقام آخر کون ہو گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مقتول مومن کے قائم مقام کو تلاش کرنے سے ہی ، اس آیت میں کسی فریق ثانی یا ولی کی عدم موجودگی میں پنہاں شارع کا منشا سامنے آ سکتا ہے ۔
مقتول مومن کے قائم مقام کی تلاش میں بنی اسرائیل آیت ۳۳ اور النساء آیت ۹۳ کا تقابلی مطالعہ کافی معاونت کر سکتا ہے ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۳ میں (وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً) کے بیان سے ، سورۃ النساء آیت ۹۳ میں (وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً) کے ذکر کی بظاہر کوئی گنجایش باقی نہیں رہتی ، کہ مقتول مظلوم ، مومن بھی ہو سکتا ہے ۔ لیکن غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل آیت ۳۳ میں مقتول کی ’’مظلومیت کی نوعیت ‘‘بیان نہیں کی گئی ۔ چونکہ مقتول مظلوم ، غیر مومن بھی ہو سکتا ہے ، اس لیے قرینہ بتاتا ہے کہ مظلومیت ، نوعیت کے اعتبار سے دنیاوی پہلو کی حامل ہے ،مثلاََ سماج میں طبقاتی کھینچا تانی کے عمل میں کوئی شخص مظلومانہ قتل ہو سکتا ہے یا کارا کاری جیسی کسی قبیح رسم کی بھینٹ چڑھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔اسی لیے شارع نے ایک طرف (بنی اسرائیل آیت ۳۳کے تناظر میں ) النساء آیت ۹۳ میں ’مومن‘ پر فوکس کیا ہے اوردوسری طرف (البقرۃ آیت ۱۷۸ کے تناظر میں )’عمد‘ پر توجہ مرکوز رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کے جواز کے بغیر ، جانتے بوجھتے مومن کو عمداََ قتل کرنا ، اللہ کے غضب اللہ کی لعنت اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کے عذابِ عظیم کو دعوت دینے والی بات ہے ۔ اس تقابلی مطالعہ سے یہ نکتہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا طبقاتی کھینچا تانی وغیرہ کے عمل میں مظلومانہ قتل ہو جائے اور وہ شخص مومن بھی ہو تو ، اس کے قاتل کے جرم کی سنگینی بہت بڑھ جاتی ہے۔ غالباََ اسی سنگینی کو باقاعدہ ظاہر کرنے کے لیے ہی، بنی اسرائیل آیت ۳۳ کے برعکس مقتول(اور اس کے ولی ) کے بجائے النساء آیت۹۳ میں قاتل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے (فَجَزَآؤُہُ جَہَنَّمُ خَالِداً فِیْہَا وَغَضِبَ اللّہُ عَلَیْْہِ وَلَعَنَہُ وَأَعَدَّ لَہُ عَذَاباً عَظِیْماً) جیسی سخت وعید بیان کی گئی ہے ۔اس وعید میں یہ معنویت بھی مستور ہے کہ چونکہ مومن قرآن کے نظامِ اقدار کا متشکل روپ یا تجسیم ہے ،اس لیے اسے عمداََ قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو حق جانتے ہوئے نہ صرف جھٹلا یا جائے بلکہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی مذموم کوشش بھی کی جائے ۔لہذا ، اس آیت سے یہ معانی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ مومن کو بلا جوازعمداََ قتل کرنا درحقیقت قرآنی اقدار پر مبنی ہیتِ اجتماعی(معاشرہ) کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اس لیے ایسے مقتول مومن کے قائم مقام یا ولی کی حیثیت مسلم معاشرے کی اجتماعیت کی نمائندگی کرنے والی مقتدر طاقت (معروف معنوں میں خلافت یا ریاست) کو ہی حاصل ہو گی۔ اس لیے ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں مقتولین کے ورثا کو ’ولی‘ کا رتبہ حاصل نہیں تھا، اگر وہ رضامندی سے بھی دیت لینے پر آمادہ ہو جاتے تو اس آمادگی کی کوئی شرعی توجیہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کیس میں ولی کی حیثیت مومنین کی معاشرت کی نمائندگی کرنے والے ادارے کو حاصل تھی جسے آج کل ریاست کہتے ہیں اور اس ریاست کے پاس بھی امریکی قاتل کو عبرت ناک مرکب سزا دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا (جیسا کہ جزا کی بحث میں ذکر ہو چکا)۔ ریاست کے پاس سزا دینے کے علاوہ کسی بھی آپشن کی عدم موجودگی سے، مقتول مومن کے ورثا کو ولی کی حیثیت نہ دیے جانے کی حکمت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شارع کا منشا اس نوعیت کے کیسوں میں ایسی انتہائی سخت سزا کا نفاذ ہے جو جرم کی سنگینی کو ممکن حد تک قریب سے ایڈریس کر سکے۔
قصاص میں ریاست کا اختیار
یہاں ضمناً ایک نکتے کی صراحت بے جا نہ ہو گی کہ قصاص کے معاملے میں ریاستی اختیار(ریاست بطور فریق) پر زور دینے والے اہلِ علم اپنے استدلال کی بنیاد سورۃ البقرۃ۲ آیت۱۷۸ پر رکھتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ البقرۃ آیت ۱۷۸ (یَا أَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْْکُمُ الْقِصَاصُ....) میں ریاست کو فریق کی حیثیت یا ریاستی اختیار، پورا معاملہ طے پا جانے کے بعد کسی قسم کی گڑ بڑ کی صورت میں (فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِکَ فَلَہُ عَذَابٌ أَلِیْم) آیت کے تکمیلی الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ تکمیلی الفاظ سے قبل کا بیان ریاست کو اصولاً (صرف اور صرف)قصاص کی تلوار اٹھائے رکھنے کا پابند کرتا ہے تاکہ اس کے سائے تلے مقتول کے ورثا اطمینانِ قلبی کے ساتھ (دھونس زبردستی کا شکار ہوئے بغیر) دیت وغیرہ کا معاملہ طے کر لیں جو شارع کا (اصلاً)مقصود و منشا ہے۔ ہماری ناقص رائے میں قتل جیسے معاملات میں ریاست کو فریق بنانے کی بنیاد سورۃ النساء۴ آیت۹۳ میں تلاش کی جانی چاہیے۔ سورۃ البقرۃ۲ آیت۱۷۸ کے بنیادی حکم میں ایسی تلاش نص میں اضافہ شمار ہوگی۔
کسی غیر ملکی پر اسلامی حدود کا نفاذ
ریمنڈ ڈیوس کیس سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی غیر ملکی پر جب کہ وہ غیر مسلم بھی ہو، کیا اسلامی حدود کا نفاذ اصولاً کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصاص و دیت کی بنیادی آیت سورۃ البقرۃ ۲آیت۱۷۸ کے آغاز میں ہی مومنین کو خطاب کیا گیا ہے (یَا أَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْْکُمُ الْقِصَاصُ فِیْ الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَی بِالأُنثَی) جس سے غیر ملکی غیر مسلم مستثنیٰ معلوم ہوتے ہیں۔لیکن یہاں مومنین کے نظمِ اجتماعی یعنی ریاست کو خطاب کرنے کی وجہ سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس مقام پر مومنین کا ذکر ان کی’ مقتدر ذمہ داری‘ کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ وہ اس حکم کی تنفیذ کو (مسلم غیر مسلم کی تفریق میں الجھے بغیر) عمومی صورت میں یقینی بنائیں۔ لیکن پھر (فَمَنْ عُفِیَ لَہُ مِنْ أَخِیْہِ شَیْْء) کے بیان میں ( أَخِیْہ) کی کیا توجیہ کریں گے؟ کیونکہ اس سے یہ سوال جنم لے گا کہ کیا قرآن مجید کے مطابق مومن اور کافر بھائی بھائی ہو سکتے ہیں؟سورۃ الحجرات۴۹ آیت۱۰ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۃٌ فَأَصْلِحُوا بَیْْنَ أَخَوَیْْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّہَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ) کے تناظر میں (جس کا مزید حصر سورۃاٰل عمران۳ آیت۱۵۶ کرتی ہے) اگر اس سوال کا جواب’نہیں‘ میں ہے تو دیت کے بیان (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْْہِ بِإِحْسَان) کے بعد اللہ کی رحمت کے خاص ذکر (ذَلِکَ تَخْفِیْفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۃٌ) کا مخاطب کوئی غیر ملکی غیر مسلم نہیں رہتا، کیونکہ یہاں تک پہنچنے کی بنیاد (بھائی) ہی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے داخلی شواہد اس کے کسی غیر ملکی غیر مسلم پر اطلاق میں مانع ہیں۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں ایک فریق مسلمان ہو اور دوسرا غیر ملکی غیر مسلم(جیسا کہ ریمنڈ ڈیوس کیس کا معاملہ ہے) اور نصِ قرآنی اس غیر ملکی غیر مسلم پر منطبق نہ ہو رہی ہو (جیسا کہ البقرۃآیت۱۷۸ کے جائزے سے معلوم ہوا) تو کیا شریعت خلا میں معلق رہے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انطباق کے حوالے سے تعطل اسی وقت سامنے آتا ہے جب قضیے سے متعلق موزوں آیت سے استدلال نہ کیا جائے۔ سورۃ البقرۃ۲ آیت ۱۷۸ کے آغاز سے یہ بات تو تقریباً طے ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں تخصیص کے ساتھ بھی مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں اصلاً ایسی مقتدر ذ مہ داری نبھانے کو کہا گیا ہے جس کی عمل داری (jurisdiction) غیر ملکی غیر مسلم تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اس پر مستزاد، ایسی آیات بھی بکثرت موجود ہیں جن میں کسی تخصیص کے بغیر خطاب کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ امر اتنا قابلِ بحث نہیں رہتا کہ غیر ملکی غیر مسلم شرعی حدود کی (jurisdiction) میں آتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف موزوں احکامات کا اطلاق ہی قابلِ توجہ اور قابلِ تنقیح قرار پاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں سورۃ النساء۴ آیت ۹۳، اطلاقی پہلو سے نہایت موزوں آیت ہے۔یہ آیت اصولی لحاظ سے یہ امر بھی واضح کرتی ہے کہ شریعت کی تنفیذ غیر مسلموں پر کی جا سکتی ہے ۔ کیونکہ اس آیت کے مطابق مومن کو عمداً قتل کرنے والا اگر خود بھی مومن ہو تو اس قبیح فعل کے بعد وہ مومن نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ النساء۴ آیت ۹۳ کا اطلاق (عمومی طور پر) دائرہ ایمان سے خارج لوگوں پر ہو تا ہے، اس لیے ایمان نہ رکھنے والے ہی اصلاً اس آیت کی عمل داری میں آتے ہیں۔
ریمنڈ ڈیوس کیس سے جنم لینے والے واقعاتی سوالات
امریکی قاتل ریمنڈ ڈیوس کی طرف سے دیت (اس کے درست یا غلط ہونے سے قطع نظر) کی ادائیگی کے معاملے میں بھی سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ شنید ہے کہ کسی اسلامی ملک (بشمول اسلامی جمہوریہ پاکستان) نے ریمنڈ ڈیوس کی دیت کا معاملہ ہی ’طے‘ نہیں کروایا بلکہ ایک قدم مزید بڑھتے ہوئے قاتل کی طرف سے دیت کی رقم اد ا کرنے کی ’سعادت‘ بھی حاصل کی ہے۔ سنا ہے کہ کسی بااثر پاکستانی مسلمان شخصیت نے بھی ’نمک حلالی‘ کرتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنے کی خوب کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کہ دھواں آگ کا پتہ دیتا ہے ، بات کچھ بھی ہو، اگر اس میں کسی قدر سچائی پائی جاتی ہے تو شخصیت موصوف اور اسلامی ریاست نے امریکی قاتل کے ’عاقلہ‘ کا کردار ادا کیا ہے جس سے ان کا ’قبلہ‘ بے نقاب ہو گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان یااسلامی ریاست، کسی غیر ملکی غیر مسلم مجرم کے لیے ’عاقلہ‘ کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں، تو ایسا کر گزرنے والوں کی بابت کیا حکمِ شرعی ہے؟
ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے متعلق ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اسے وسیع تر قومی مفاد میں رہا کیا گیا ہے۔ اس لیے عدالتی کاروائی محض ایک کاروائی تھی، مقصد اسے ہر صورت رہا کرنا تھا۔ لہذا اس پورے معاملے کو خالصاً قانونی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر قومی مفاد کی یہ منطق مان بھی لی جائے اور یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں جو کرتب دکھائے ہیں اس سے امریکہ بہت مرعوب ہو اہے اور اپنے بِل میں دبک کر بیٹھ گیا ہے تو پھر بھی ایک سوال موجود رہتا ہے کہ امریکی قاتل کی رہائی کے لیے اسلامی حدود کا غلط استعمال کیوں کیا گیا؟ کیا کسی اور ذریعے سے اسے رہا نہیں کیا جا سکتا تھا؟یا پھر اس کی رہائی کے ساتھ یہ مقصد بھی شامل تھا کہ اسلامی حدود کی تضحیک کی جائے اور انہیں متنازعہ بنایا جائے؟ یہاں ایک اصولی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی حدود کو ریاست کی تزویراتی مہمات (strategic adventures) کی بھینٹ چڑھایا جا سکتا ہے، چاہے یہ مہمات مبنی بر قومی مفاد ات ہی ہوں؟ اگر اس سوال میں کسی بھی درجے میں سنجیدگی پائی جاتی ہے تو آج کے اہلِ علم کو اسلامی حدود کے مطالعات کی نئی جہتیں متعارف کروانی ہوں گی۔
امریکی قاتل ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے معاملے میں اسلامی حدود کو جس طرح ’برتا‘ گیا ہے اس سے ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا سوال جنم لیتا ہے کہ کیا مومنین کا کوئی ایسا نظمِ اجتماعی ، جو فی الواقعی مقتدر حیثیت کا حامل نہ ہو، اپنی نام نہاد عمل داری (jurisdiction) میں اسلامی حدود کے نفاذ کا شرعی حق رکھتا ہے؟ ہماری رائے میں تو اصولیین اور فقہا کو(جدید صورتِ حال کے تناظر میں) مومنین کے نظمِ اجتماعی کی اس کم از کم مقتدر حیثیت(prerequisite sovereignty) کا باقاعدہ تعین کرنا چاہیے جس کی عدم موجودگی میں حدود کے نفاذ پر اصولاً پابندی عائد ہو، تاکہ اسلامی حدود کا مذاق نہ اڑایا جا سکے۔ اور اگر یہ طے پا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایسی کم از کم مقتدر حیثیت (prerequisite sovereignty) کا حامل نہیں ہے تو اسلام پسند حلقوں کو شریعت کے نفاذ کے بجائے نافذ شدہ حدود کی تنسیخ کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام پسند حلقے ایسی جرات اور بالغ نظری کا مظاہرہ کر پائیں گے؟ یہ حلقے ریمنڈ ڈیوس قضیے کو دبے لفظوں میں ’جرمِ ضعیفی کی سزا‘ قرار دے رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں جب تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا’مردانہ ضعف‘ دور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کے لیے اس ریاست میں حدود کے نفاذ کی جدوجہد کرنے والوں کو دیت کے ’حشرنشر‘ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے اور اپنی ترجیحات کا ازسرِ نو تعین کرلینا چاہیے۔
کورٹ میرج: چند قانونی اور معاشرتی پہلو
چوہدری محمد یوسف ایڈووکیٹ
چودھری محمد یوسف ایڈووکیٹ
شفقت رضا منہاس ایڈووکیٹ
ہمارے ہاں کورٹ میرج کا ایک عام تصور پھیلا ہوا ہے، حالانکہ اس کا نہ قانونی وجود ہے اور نہ ہی کوئی بنیاد۔ (البتہ ایک رائے کے مطابق non-believers یعنی غیر اہل ایمان کا چونکہ کوئی خاندانی نظام دویعت شدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے بعض نظائر کی بنیاد پر کورٹ میرج کا تصور موجود ہے۔ یہ واضح رہے کہ غیر اہل ایمان میں مسلمان، ہندو، سکھ، یہودی اور عیسائی شامل نہیں۔ اس طرح پاکستان میں ایسے غیر اہل ایمان کی تعداد چوونکہ برائے نام بھی نہیں، لہٰذا اگر اس رائے کے مطابق ایسا کو تصور ہو بھی تو اس کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔) اس کے باوجود یہ تصور عام سطح سے لے کر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک نہایت مہربان اور عزیز دوست نے مجھے فون پر یاد کیا۔ فرمانے لگے کہ ’’میری بیٹی نے ملک کی ایک بین ا لاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں ایل ایل ایم کی کلاس میں داخلہ لیا ہے۔ اس کے لیے مقالے کا عنوان ہے: Court marriage and its effects upon family in Pakistan.۔ آپ اس عنوان کو خاکہ تحقیق بنانے میں مدد کریں۔‘‘ میں حیران ہوا کہ ایل ایل ایم کی طالبہ کے استاد، اتنی بڑی یونیورسٹی میں کم از پی ایچ ڈی تو ہوں گے۔ پی ایچ ڈی بھی کسی گھوسٹ یونیورسٹی سے نہیں، بلکہ مسلمہ یونیورسٹی سے ہوں گے، مگر وہ پاکستان کے قوانین کے بارے میں عام سطح کے شخص کی طرح اس واہمے میں مبتلا ہیں کہ کورٹ میرج کا کوئی باقاعدہ عدالتی ادارہ موجود ہے۔
میں نے اس عزیزہ پر واضح کیا کہ مذکورہ عنوان نہیں بنتا اور وجہ یہ ہے پاکستان میں کورٹ میرج کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مجھے بچی نے بتایا کہ ہمیں استاد صاحب نے کہا ہے کہ مختلف عدالتوں کو وزٹ کر کے کورٹ میرجز کے بارے میں ڈیٹا جمع کیا جائے۔ میں نے واضح کیا کہ طالب علم کے طور پر عدالت اسے اس طرح کے استفسار پر رعایت دے سکتی ہے، ورنہ عدالت کو نکاح رجسٹرار یا نکاح خواں کی سطح پر لانا عدالت کے وقار کی نفی ہو گی۔ کوئی جج اسے سنجیدہ لے سکتا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر استفسار کے دوران، یونیورسٹی پروفیسر صاحب کا حوالہ آیا تو ایسا نہ ہو کہ اس سے پروفیسر صاحبان کی ڈگریوں کی پڑتال کا سلسلہ چل پڑے۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے نام پر کاروبار اور کاروباری مفادات کے تحفظ کی صورت کا اندازہ کرنا ہو تو بورڈ آف گورنرز کے خلاف طلبہ اور اساتذہ کی ایجی ٹیشن کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کالجوں میں تعلیم، نام کی حد تک رہ گئی ہے۔ پروفیسر صاحبان کی ایک تعداد تدریس کے بجائے صرف تنخواہ وصول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔
کورٹ میرج کے تصور کے بے بنیاد ہونے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ قانون کی رو سے نکاح ایک معاہدہ ہے۔ عدالت کسی بھی معاہدے کی تشکیل میں حصہ دار نہیں ہوتی۔ کسی عدالت کو اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ البتہ معاہدہ تکمیل پا جائے تو معاہدے کی شرائط کو نافذ کرنے کا اختیار عدالت کو حاصل ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی دادرسی فراہم کی جا سکتی ہے۔ معاہدہ کی تشکیل بدوں کسی عدالتی مداخلت یا سہولت کے، فریقین کا اپنا کام ہے۔ وہ اس میں مکمل طور پر آزاد ہیں، مگر عدالت معاہدے کی تشکیل کے مرحلہ میں کوئی کردار ادا کرنے کی کسی طرح مجاز نہیں۔
البتہ یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کورٹ میرج کے بارے میں جو واہمہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ عام طور پر جس وقت کوئی لڑکی اور لڑکا اپنے خاندان سے بغاوت کر کے شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ میرے جیسے کسی وکیل سے رجوع کرتے ہیں۔ میرے دوست بھاری فیسیں وصول کر کے کورٹ میرج کے نام پر ایک ڈرامہ ترتیب دیتے ہیں۔ بالعموم اس ڈرامے کی صورت اس طرح ہوتی ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعات 107/151 کے تحت نقص امن کے اندیشے یا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 506 کے تحت مجرمانہ تخویف کا استغاثہ مرتب کر کے عدالت میں دائر کیا جاتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ نمبر 200 کی رو سے استغاثہ دائر کرنے پر مجسٹریٹ فوری طور پر مستغیث کا بیان قلم بند کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ استغاثہ چونکہ لڑکی کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا بیان عدالتی ریکارڈ پر آ جاتا ہے۔ استغاثے اور بیان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہر دو بالغ ہیں، (بلوغت کا کوئی دستاویزی ثبوت استغاثے کے ساتھ شامل کر کے فائل کا پیٹ بھرا جاتا ہے)، وہ بالغ ہونے کی وجہ سے شادی کرنے کے مجاز ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے آزاد مرضی سے باہم شادی کی ہوئی ہے اور بطور میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ان کے والدین یا دیگر قریبی رشتہ دار اس شادی کے خلاف ہیں، چنانچہ وہ طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ بیان میں کہا جاتا ہے کہ وہ مستغیثہ کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہاں تک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اسے فروخت کرناچاہتے ہیں۔ بلا شبہ اس کا استثنائی صورتوں میں امکان ہو سکتا ہے۔ یہ کہاجاتا ہے کہ والدین اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں یا جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ استتغاثے میں استدعا کی جاتی ہے کہ والدین یا مذکورہ رشتہ داروں کو طلب کر کے سزا دی جائے یا نقض امن کے اندیشے کے تحت حفظ امن کی کارروائی کی جائے۔ اس طرح کا بیان ریکارڈ کرانے کے بعد دائر کیس کی پیروی نہیں کی جاتی۔ استغاثے اور بیان کی مصدقہ نقول حاصل کر لی جاتی ہیں۔ یہ عدالتی نقول ان کے خلاف بعد میں پولیس کے ذریعے اغوا وغیرہ کی ممکنہ کارروائی میں موثر دفاع بن سکتی ہیں۔ اس اہتمام سے ہمارے دوست وکلا کہہ دیتے ہیں کہ عدالت میں ان کی شادی کی توثیق یا تصدیق ہو گئی ہے۔
وکلا بھائیوں کی جانب سے اس طرح کی نام نہاد کورٹ میرج کی ایک دوسری صورت دعویٰ اعادۂ حقوق زن و شوئی کی ہوتی ہے۔ لڑکے کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کا خاوند ہے، اس کا باقاعدہ نکاح ہوا ہے اور نکاح میں لڑکے اور لڑکی کی آزاد مرضی شامل تھی۔ دونوں بالغ ہیں، دونوں میاں بیوی کے طور پر رہنے کے خواہش مند ہیں، مگر لڑکی حقوق زوجیت ادا کرنے سے گریزاں ہے اور لڑکی کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کا دباؤ اس گریز کا باعث ہے۔ لہٰذا لڑکے کے حق میں اور لڑکی اور رکاوٹ ڈالنے والے رشتہ داروں کے خلاف اعادۂ حقوق و زن و شوئی کی ڈگری جاری کی جائے۔ یہ دعویٰ دائر کر کے تاریخ پیشی مقرر کروائی جاتی ہے۔ پھر اگلے روز ہی لڑکی کی جانب سے مثل طلب کرا کے دعویٰ کے تمام مندرجات تسلیم کرا ئے جاتے ہیں اور کیس ڈگری کرا لیاجاتا ہے۔
اس طرح کے مقدمے کی ایک اور صورت استقرار حق کی ہوتی ہے۔ اسے فنی طور پر jactitation of marriage کہتے ہیں۔ اس دعوے میں یہ کہانی پیش کی جاتی ہے کہ فریقین کے مابین باقاعدہ نکاح ہوا ہے اور لڑکا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لڑکی کا باقاعدہ خاوند ہے، مگر لڑکی خاندانی دباؤ کی وجہ سے شادی کو تسلیم نہیں کرتی۔ دعویٰ دائر ہونے کے بعد تاریخ مقرر ہونے کے ایک دو روز بعد ہی مثل طلب کروا کے لڑکی کو پیش کیا جاتا ہے اور دعوے کے مندرجات کو تسلیم کراتے ہوئے کیس ڈگری کروا لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی تسلیمی ڈگری کے لیے لڑکی کی جانب سے ایک علیحدہ وکیل پیش کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لڑکے کا وکیل لڑکی کی جانب سے پیش نہیں ہو سکتا۔ ایسی صور ت میں لڑکے کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل چونکہ پورا ڈرامہ ترتیب دیتے ہیں، اس کے لیے ان کو بھاری فیس وصول ہوتی ہے، البتہ لڑکی کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل کو سازشی طور پر تیار کر کے پیش کیاجاتاہے، اس لیے ان کو برائے نام فیس ادا ہوتی ہے۔
اس سلسلے میں، میں اپنا ایک تجربہ بیان کر دینا بر محل خیال کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست اپنے محکمے سے رخصت لے کر وکالت کے شوق میں میرے ساتھ آ شامل ہوئے۔ ان کے ایک قریبی رشتہ دار مجسٹریٹ تھے۔ انہوں نے اسی طرح کا ایک کیس بک کیا اور ہم دونوں نے کیس تیار کیا اور مذکورہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کر دیا۔ اب ہم مستغیثہ کے بیان کے لیے عدالت میں گئے تو اس پر پیشی ڈال دی گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہو۔ قانون کے لازمی تقاضے پر زور بھی دیا مگر مجسٹریٹ چونکہ اس طرح کی پریکٹس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ بیان قلم بند کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے قانون کی پابندی کے بجائے اپنے ضمیر کا لحاظ رکھا۔ ہم دونوں کی مولویت شرمندہ ہوتی رہی، مگر ہم چند ٹکوں کے لیے قانونی تقاضے پر زور دیتے رہے۔
اس طرح کے واقعات ایک مدت مدید سے چلے آرہے ہیں۔ وکلا ذہین لوگوں کا پیشہ ہے۔ وہ اس طرح کی کورٹ میرج کی اور بھی صورتیں تراش سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان کا اپنی چالیس سالہ پریکٹس کے باوجود تصور نہ کر سکوں۔ اس لیے اس تحریر میں، میں ایسی تمام صورتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال کورٹ میرج کا تصور ایسے مقدمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر اگر پس منظر کی اس صورت حال سے شناسا نہ ہوں تو میں انہیں زیادہ قصور وار نہیں ٹھہرا سکتا، البتہ انہیں صورت حال سے آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔
اس صورت حال کی بنیاد اور پس منظر میں لڑکے اور لڑکی کی جانب سے اپنے اپنے خاندانوں سے بغاوت کا وجود لازمی عنصر ہے۔ خاندان سے بغاوت کے بعض کیسوں کے پس منظر میں خاندانی جبر کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں ونی کی رسم اور قرآن کے ساتھ شادی، والدین کی جانب سے لڑکی کو فروخت کرنے کی صورتیں بھی ممکن ہیں۔ یہ صورتیں خاندان سے بغاوت کا اخلاقی یا قانونی جواز بن سکتی ہیں یا نہیں، ایک ایسا سوال ہے جو اہل فقہ سے متعلق ہے۔ ہمارے حلقے کے بہت سے اہل علم جہاد بالسیف کے لیے ریاستی آشیر باد کو شرطِ لازم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت یاخروج کو بڑی سخت شرائط میں جکڑتے ہیں۔ خاندانی نظام کو اس طرح کا تحفظ دینے میں نکاح کے لیے لڑکی کی جانب سے ولی کی تقرری کے بارے میں اہل اجتہاد کیا موقف اختیار کریں گے، اس بارے میں ان کے درمیان کھلا مباحثہ ہونا چاہیے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس حفیظ اللہ چیمہ نے مشرف کے دور میں ایک فیصلہ دیا تھا جس کی رو سے نکاح کے لیے لڑکی کی جانب سے ولی کا تقرر لازمی قرار دیاگیا۔ ان کا فیصلہ قیاس پر مبنی نہیں تھا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد (لا نکاح الا بولی) پر مبنی تھا۔ لیکن بعد میں مملکت اسلامی جمہوریہ میں، روشن خیالی کی لہر تیز اور طاقت ور ہوگئی، لہٰذا اس کے برعکس نقطہ نظر غالب آ گیامگر جسٹس حفیظ اللہ والے فیصلے کا کیا بنا، یہ معلوم نہیں۔ اسے اگر منسوخ کیا گیا ہوتو اسے میڈیا میں جگہ نہیں مل سکی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی باقاعدہ اور حتمی سماعت نہ ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ حاکم خان کیس میں متنازعہ نکات پر حبیب وہاب الخیری کی رٹ پیٹیشن کے ساتھ ہائیکورٹ میں یہی کچھ ہوا تھا۔ اس درخواست کو جسٹس شیخ خضر حیات نے تعطیلات میں، سائل کو دس روز سن تک کر سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ بعد میں اس کی کبھی سماعت نہیں ہوئی۔
جناب عمار خان ناصر کی تازہ تحریر ماہنامہ الشریعہ کے دسمبر ۲۰۱۰ء کے شمارے میں موجودہے۔ اس میں ان کی مجتہدانہ بصیرت بڑی توانا نظر آتی ہے، مگر ولی کے تقرر کے بارے میں انہوں نے اختصارکے پیش نظر صرفِ نظر سے کام لیا ہے یا شاید میں ان کے مضمون کو زیادہ غور سے پڑھ نہیں سکا۔ ان کو اس پہلو پر بھر پور اظہار کرنا چاہیے۔ بہرحال خاندان سے بغاوت کی حدود اور شرائط کا تعین باقی ہے۔ اس مسئلے میں خودکچھ نہیں کہنا چاہتا، البتہ یہ بات بہت واضح ہے کہ خاندان ہماری سوسائٹی کی ایک نہایت اہم قدر ہی نہیں، اثاثہ بھی ہے۔ اسے آسانی سے تج دینا ممکن ہے اور نہ ہی جائز۔ جو لڑکی بھی اس تحفظ اور سہارے سے محروم ہو کر باہر آئے گی، اس کا سامنا سوسائٹی میں موجود بھیڑیوں سے ہوگا۔ ایسی صورتوں کی پیش بندی یا مداوا ہمارے سوشل سائنسدانوں کی ذمہ داری ہے۔ اختصار کی خاطر ایک ٹی وی شو کا ذکر برمحل خیال کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے اس شو میں ہماری اقدار کے تحفظ میں جتنا موثر انداز اختیار کیا گیا، وہ لاکھ تقریروں، تحریروں اور درسوں پر بھاری ہے۔
اے ٹی وی پر ہفتے کے پہلے پانچ روز ایک شو ہوتاہے جس کا نام ’’مارننگ ود فرح حسین‘‘ Morning with Farah Husain ہے۔ میں کبھی کبھار یہ شو جزوی طور پر دیکھ لیتا ہوں۔ فرح حسین کو اپنے شو میں ہر طرح کے روپ میں آنا پڑتا ہے۔ اکثر و بیشتر ان کے روپ مجھے پسند نہیں آتے۔ وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ ہماری معاشرتی اخلاقیات کے فروغ و تحفظ کے بارے میں ان سے میرے اندازے کے مطابق کبھی لغزش نہیں ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یادہے کہ چند سال پہلے ایک پروگرام میں انہوں نے لاہور کی ایک خاتون کو پیش کیا تھا۔ یہ خاتون کئی شہروں میں بیوٹی پارلرز جیسے کاروبار کے وسیع سلسلے کی مالک اور آسودہ حال خاتون تھی۔ راولپنڈی کے ایک شخص نے کسی نہ کسی طرح اس خاتون سے شادی کر لی۔ دو تین بچے ہوئے۔ راضی خوشی گزر اوقات کے ایک عرصہ بعد فریقین کے ما بین نا چاقی ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ اس سب کچھ کے باوجود مرد نے خاتون کاپیچھا نہ چھوڑا۔ بچے خاتون کے پاس رہے۔ وہ اسے بچوں کے حوالے سے بلیک میل کر کے ایک مدت تک دولت بٹورتا رہا۔ بلیک میلنگ کی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ جب یہ تمام حدیں پار ہوگئیں تو ایک رات وہ بچوں سے ملنے کے بہانے لاہور آیا۔ خاتون کے گھر بچوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بھی اس نے بلیک میلنگ کی کوشش کی، مگر جب کچھ حاصل نہ ہوا توجاتے ہوئے خاتون کے چہرے پرتیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ اس کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر کے آیاہوا تھا۔ اس کی داستان ستم فرح حسین نے خود تفصیل سے بیان کر دی۔ پھر فرح حسین نے، اس خاتون کو ٹی وی اسکرین پر پیش کیا۔ خاتون نے چہرے سے برقعے کا نقاب ہٹایا اور اپنا مسخ شدہ چہرہ ناظرین کے سامنے پیش کیا اور روروکر التجا کی کہ لو میرج کے خبط میں گمراہ ہوکر بھائیوں، والدین یعنی خاندان کے تحفظ سے آزادی کا آپشن استعمال نہ کرنا۔ سوسائٹی کے بھیڑیوں سے بچنے کی واحد صورت خاندان کا ادارہ ہے۔ اس سے باہر نکلنا مکمل بربادی کو دعوت دینا ہے۔
کاش فرح حسین کے اس شو کی سی ڈی سوسائٹی میں عام ہو۔ ہمارے ہاں منصب و ارشاد والے توبین الاقوامی سطح پر سیمیناروں میں ابھی یہ طے نہیں کر سکے کہ جدیدذرائع ابلاغ (ٹی وی، سینما، انٹرنیٹ) کا مثبت استعمال جائزہے یا نہیں، (دیکھیے: ماہنامہ الشریعہ اکتوبر ۲۰۰۵ء میں روئیداد سہ روزہ بین الاقوامی سیمینار فقہائے اسلام، منعقدہ لکھنو اور ماہنامہ الشریعہ نومبر ۲۰۰۵ میں اس سیمینار کے حوالے تفصیلی تبصرہ منجانب مرتب) مگر میں تکرار کے ساتھ یہ کہے بغیرنہیں رہ سکتاکہ فرح کا شو اپنے گہرے تاثر کے لحاظ سے لاکھ تقریروں اور درسوں پر بھاری ہے۔ ہمارے اہل اجتہاداپنے گھروں یا اداروں میں ٹی وی رکھنے سے خائف ہیں، مگر ادھر ادھر خوددیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح کے خوف زدہ مجتہد سوسائٹی میں رسمی کردار سے زیادہ کتنا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں! جب ہم مارکیٹوں میں وڈیو اور آڈیو کیسٹس اور سی ڈیزکے سیلاب کو دیکھیں تو ان میں ایک طرف فحش، عریاں فلموں اور گانوں کا سیلاب ہے تو دوسری طرف فرقہ وارانہ تقریروں کا طومار ہے۔ کچھ علمی حلقے واقعی اور عملی مسائل سے دور رہ کر لغت ہائے حجازی کے حلقے سجائے ہوئے ہیں۔ سوسائٹی کے حقیقی مسائل اور دکھ درد کا ادراک اور مثبت، موثر نوعیت کی چیزوں کا مکمل فقدان ہے۔
نکاح اور شادی کے قوانین، خاندان کے یونٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ یہ مقصد اسلام کے قانونِ نکاح ہی میں نہیں بلکہ ہر دیگر قوانین اور تہذیبوں میں پایا جاتا ہے۔ خاندان کا تقدس اور اس کا احترام اور اس کی مضبوطی کی خواہش ہر تہذیب میں موجود ہے۔ مغربی تہذیب جس کے بارے میں مسلمانوں میں آزادہ روی کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے مغرب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کردار کشی پر مبنی لٹریچر ہے۔ اگر مغربی تہذیبوں کا بلا تعصب مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہر تہذیب کی طرح مغربی تہذیب بھی خاندان کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اس بارے میں امریکی تہذیب بہت زیادہ آزاد رو سمجھی جاتی ہے، مگر امریکی لٹریچر میں خاندان کی اہمیت کے شواہد بڑے مضبوط صورت میں موجود ہیں۔ مغربی تہذیب میں ہمیشہ سے خاتون کو گھر کی رونق ہی خیال کیا جاتا تھا۔ اندرون خانہ خاندان کے استحکام، بچوں کی تربیت، خاوند کی آسودگی کی ذمہ داریاں مسلمہ طور پر عورت پر ہی عائد ہوتی تھیں۔ عورت کا ناگزیر صورت حال کے سوا گھر سے نکلنا مغربی تہذیب میں بھی اتنا ہی معیوب تھا جتنا کہ اسلامی تہذیب میں تھا اور ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس صورت حال میں تبدیلی کی شروعات ہوئیں۔ جنگ کی وجہ سے مردوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سالہا سال تک گھر سے دور جنگوں میں مصروف رہے۔ اس سے مغربی ممالک کی اقتصادی نظام میں زبردست خلا پیدا ہوا۔ دفتروں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مردوں کی قلت کو دور کرنے کے لئے عورتوں کو گھر سے نکلنا پڑا۔ اس طرح تبدیلی کا عمل شروع ہوا۔
تبدیلی کے اس عمل میں مغربی سوسائٹی کی پست اخلاقی اقدار نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے مسلمان مبصرین توازن ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ نتیجتاً وہ مغربی سوسائٹی میں اس پستی کے خلاف رد عمل کا حوالہ نہیں دیتے۔ اس بارے میں مثال کی ضرورت ہو تو سید مودودی کی مغربی تہذیب پر تنقید کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ سید کی زبردست تصنیف ’’پردہ ‘‘ ہے۔ (فیملی لاز پر سید مودودی ایک کتاب ’’حقوق الزوجین‘‘ کورٹ میرج کے حوالے سے تو خالی ہے، مگر اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک معرکہ آرا کتاب ہے۔ اردو زبان میں میرے مطالعے میں اس سے زیادہ دقیق اور کوئی کتاب نہیں۔ یہ کتاب مولانا کی گنتی کی چند تصانیف میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب ہمیشہ اپڈیٹ رہے گی۔) اس میں انہوں نے پردہ کے بارے میں اسلامی احکامات کاشاندار طریقے سے دفاع کیا ہے۔ مولانا مودودی کا انداز بیان اتنا پر زور اور موثر ہے کہ پڑھنے والے کو ذہنی طور پر قائل ہونا پڑتا ہے، یہاں تک کے جدید تعلیم یافتہ، مغربی تہذیب کے اثرات کے تحت آنے والے بھی مولانا کے زور بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی کتاب میں مولانا نے مغربی تہذیب کی عریانی کے بخیے تار تارکر کے رکھ دیے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو مغربی حوالوں سے update کیا جائے۔ مغرب نے اپنے ہاں تہذیبی صورت میں تبدیلی کا جائزہ لیا ہے۔ ہمیں اس جائزے کو کسی صورت فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب میں اخلاقی اقدار خاص طور پر خاندان کے یونٹ کے بارے میں مثبت لٹریچر کو ہر صورت اہمیت دینا چاہیے۔
مجھے امریکی لٹریچر کے بارے میں وسیع رسائی تو حاصل نہیں لیکن اتفاق سے، ایک کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس میں دیے گئے مواد نے مجھے توجہ دینے پر مجبور کر دیا۔ اس موقعہ پر میں چند حوالے دے کر قارئین کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام Making Americaہے۔ یہ کتاب ۱۹۸۷ میں واشنگٹن سے سرکاری اطلاعاتی ایجنسی نے شائع کی ہے۔ کتاب کی ترتیب Luther S. Luedtke نے کی ہے۔ کتاب کا تیسرا حصہ اوپر ذکر کردہ پہلو سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں اعداد و شمار کے ساتھ خاندانی یونٹ کے زوال کا بہت مکمل جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ امر تو یقینی ہے کہ خاندان سے بغاوت کا نتیجہ معاشرتی تباہی کے سوا کچھ ممکن ہی نہیں۔ یہ نتیجہ مغرب اور مشرق میں ایک جیسا ہے۔ بغاوت کا ثمر امریکہ اور پاکستان میں ایک ہی پیدا ہوگا۔ امریکہ میں اعداد و شمار کی مدد سے جائزہ لیا گیا ہے، جب کہ پاکستان میں اعداد و شمار اور جائزے کا عمل ناپید ہے۔ اگر اعداد و شمار کسی طرح مہیاہو جائیں تو ان کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ یہاں سروے مکمل اعداد وشمار کے بجائے نمائندہ یا منتخب افراد یا حلقوں کی بنیادپر مرتب کیے جاتے ہیں اور ان پر نتائج کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بہر صورت ہم امریکی جائزہ سے اقتباسات پیش کر کے پاکستان میں قیاس پرنتائج مرتب کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک فرق ضرور رہے گاکہ ہمارے ہاں خاندان کے حوالے سے اخلاقی اقدار بے حد مضبوط ہیں۔ ان کے زوال کی رفتار میرے خیال میں بہت سست ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا مغربی اقدار کو فروغ دینے کے لیے جو کچھ کررہا ہے، بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال پی ٹی وی ہوم پر حال ہی میں دکھائے جانے والے ایک ڈرامے ’’زنداں‘‘ کی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک نفسیاتی مریضہ کو split personality (دوہری شخصیت) کے طور پر پیش کیا گیا۔ عارضہ کی وجہ یہ ظاہر کی گئی کہ مریضہ اپنے جائز بیٹے اور شادی کو وہم کے اعتبار سے ناجائز خیال کرنے لگی۔ علاج میں، اس کے شوہر کو یہ تدبیر بتائی گئی کہ وہ شادی اور اولاد کو ناجائز تسلیم کر کے معافی مانگے اور بار بار کی معافی کے بعد، نفسیاتی طور پر اپنی بیمار بیوی کو دوبارہ شادی کے لیے اسے راضی کرے۔ اس طرح مریضہ کے بارے میں دکھایا گیا کہ وہ ذہنی عارضے سے صحت یاب ہو گئی۔ یہاں ڈرامہ نگار کی مہارت کی داد تو دینا پڑتی ہے مگر پس منظر میں فکری پراگندگی جھلکتی ہے۔
ہمارے ہاں کوئی خود کتنا ہی بد کردار ہو، مگر اپنے خاندان اور بیٹیوں کو بد کردار بنانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ نیکی اور برائی کی مقدار میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے بسیرے بدلتی ہے۔ اچھی یا بری اقدار پر کسی کا اجارہ نہیں۔ آج فرض کیجیے میں شرافت کا امین ہوں تو کل کو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قدر میرے گھر سے رخصت ہو کر کسی برے شخص کے ہاں ہدایت کا ذریعہ بن کر بسیرا کر لے۔
لیجیے امریکی سوسائٹی میں خاندان کے زوال کی کہانی امریکیوں کی زبانی سن لیں۔
As late as the 1950s, more than 70 percent of all American families comprised a father who worked, a mother who stayed at home to take care of the children. By 1980, that description applied to only 15 percent of all families. In the same year, birth rates declined precipitously. At the height of the baby boom, the average family had more than three children. By 1980, that figure had fallen to less than 1.6 children, the reproduction level required for zero population growth. (p. 265)
The divorce rate climbed more than 100 percent in the twenty years after 1960 and by 1980 more than two out of five marriages were expected to end in divorce. (p. 265, 266)
By the 1970s, these trends in behavior and attitude had begun to reinforce each other. College educated women--those most affected by the rise in feminist conscienceness--increasingly declared that a career was just as important a priority as marriage. (p. 264)
Women must boldly announce that no job is more exacting, more necessary , or more rewarding than that of housewife and mother. (p. 262)
As soon as the war ended, business leaders, politicians and social commentators insisted that women must recapture their traditional role as housemakers. (p. 261)
During the war years, the female labor force increased by 57 percent, and the proportion of women who were employed leaped from 25 percent to 36 percent. When the war began, it was expected that virtually all the new workers would return to home as soon as the war was over. Four years later, more than 80 per cent told the government pollsters that they wanted to stay on the job. (p. 261)
Women who, a few years before, had been told it was a mortal sin to leave the home and take a job were now urged as a matter of patriotic necessity to help win the war by replacing a soldier gone to the front. Between 1941 and 1945 over six million women took jobs for the first time, the majority of them married and over thirty. (p. 261)
In effect, a married middle-class white women who wished to work was an anomaly, acting in violation of both her social status and the attitude of dominant culture. As the anthropologist Martraret Mead observed in 1935, a young woman contemplating a career had two choices. Either she proclaimed herself ''a woman'' and therefore less an achieving individual, or therefore less a woman. She could not do both, and if she chose to follow the second option, she took the risk of losing for ever the chance to be a ''loved object, the kind of girl whom men will woo and boast of, toast and marry.'' (p. 260-261)
By the end of 1930s state, local and national authorities all endorsed discriminatory treatment against married women seeking employment. As one congressional representative declared, a woman's proper place was in the home, not taking job away from a male breadwinner. (p. 260)
Adlai Stevenson's injunction to Smith College class of 1957 that women's primary role as citizens should be to influence men through their positions as ''house wives and mothers'' as a latter day manifestation of the same cultural world view that guided colonial America. (p. 259)
In the word of one matron quoted in an eighteenth century news paper, ''I an married, and I have no other concern but to please the man I love; he is the end of every care I have; If I dress, it is for him, if I read a poem or a play, it is to qualify myself for a conversation agreeable to his taste.''
آخر پر یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتاہوں کہ میں باغی ہوں۔ اپنے گرد و پیش سے بغاوت میری سرشت ہے۔ میں اپنے آس پاس کی فسوں کاری کو توڑ دینا چاہتا ہوں ۔ میں سوسائٹی میں ہر طرح کے جبر، ظلم، بد دیانتی، کرپشن، مفاد پرستی، گروہ بندی، سازش، جماعتی وغیر جماعتی تعصب کے خلاف بغاوت پر ہمہ تن اور ہمہ وقت آمادہ ہوں، مگر میں کبھی اقدار کا باغی نہیں ہوا۔ خاندان سے کبھی بغاوت نہیں کی۔ ذاتی طور پر خاندانی جبرکو بھی قبول کیا، بہت نقصان بھی اٹھایا مگر بڑوں کے احترام میں کوتاہی نہیں کی۔ خاندان کی سطح پر سوسائٹی میں پائے جانے والے ظلم کے خلاف نوجوان اور ناپختہ ذہنوں کو بغاوت کی راہ دکھلانا میرے نزدیک کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ البتہ سوسائٹی کے لیے ہر طرح کے ظلم، جبر اور بے انصافی کے خلاف بغاوت لازم ہے۔ اس میں خاندان کا جبر پہلی ترجیح کے طور پر ہے ۔ اس بغاوت کی سربراہی اورقیادت پختہ ذہن، تجربہ کار، راسخ العقیدہ اور صاحب کردار لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ایسی بغاوت ہر صورت خیر ہی خیر ہوگی۔ البتہ بغاوت میں سودا بازی اور مصلحت کی گنجائش کسی اجتہاد سے نکالی جا سکتی ہو تو پھر منفی قوتوں کے لیے راہ چھوڑ کر اپنا وقار بچا لینا بہتر ہو گا۔
توہین رسالت کے مسئلے پر ایک مراسلت
محمد عمار خان ناصر
(گزشتہ دنوں توہین رسالت کی سزا سے متعلق بعض اہل علم ودانش کے ساتھ مراسلت میں راقم کو اس کے بعض اہم پہلووں کی توضیح کا موقع ملا جسے نقد ونظر کے لیے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ مدیر)
(۱)
مکرمی ! السلام علیکم ورحمۃ اللہ
آپ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے حوالے سے میری گزارشات حسب ذیل ہیں:
۱۔ آپ کے پہلے نکتے کا حاصل میرے فہم کے مطابق یہ ہے کہ عہد رسالت میں مختلف افراد کو توہین رسالت کی جو سزا دی گئی، اس کی علت محض توہین نہیں بلکہ قبول حق سے انکار بھی تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست مخاطب ہونے کی وجہ سے، پہلے ہی سزاے موت کے مستحق تھے جبکہ ان کی طرف سے توہین وتنقیص کے رویے نے ان کے اس انجام کو مزید موکد کر دیا تھا۔ مجھے اس احتمال میں زیادہ وزن دکھائی نہیں دیتا۔ پیغمبر کے زمانے میں خود پیغمبر کے سامنے سرکشی اور عناد کا رویہ اختیار کرنا یقیناًمعاملے کو زیادہ سنگین بنا دیتا ہے، لیکن اصل جرم جس پر سزاے موت دی گئی، وہ ’محاربہ‘ اور ’فساد فی الارض‘ تھا اور اس کے لیے بیان کیا جانے والا ضابطہ تعزیرات پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ شریعت کا ایک عام قانون ہے۔ مسلمانوں کی ریاست میں اگر کوئی غیر مسلم ان کے پیغمبر یا مذہب کے بارے میں سرکشی کے انداز میں علانیہ توہین وتنقیص کا رویہ اختیار کرتا اور اس پر مصر رہتا ہے تو وہ یقینی طور پر محاربہ اور فساد فی الارض کا مرتکب ہے جس پر اسے نشان عبرت بنا دینا واضح طور پر آیت محاربہ کا تقاضا ہے۔
۲۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس جرم پر سزا دینے کے لیے عدل وانصاف کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہییں اور باقاعدہ عدالتی کارروائی کے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جانا چاہیے تو یہ بات بالکل درست ہے اور میں اس پر الگ سے ایک تحریر لکھ رہا ہوں جو امید ہے کہ ان شاء اللہ جلد مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سزاے موت کو لازم قرار دینے کے بجائے قانون میں متبادل سزاؤں کی گنجائش رکھے جانے پر بھی میں اپنا نقطہ نظر ’’حدود وتعزیرات‘‘ میں واضح کر چکا ہوں۔ میں اس باب میں احناف کے نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں جو عام حالات میں اس جرم کو مستوجب قتل نہیں سمجھتے۔ واللہ اعلم
(۲)
برادرم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ
امید ہے مزاج بخیر ہوں گے اور آپ دلچسپی سے تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گے۔
توہین رسالت اور اس پر مواخذہ سے متعلق آپ نے جو سوالات لکھے ہیں، اپنے ناقص فہم کے مطابق ان کا جواب تحریر کر رہا ہوں۔
پہلے سوال سے متعلق عرض ہے کہ کسی قول یا عمل کا فی نفسہ خدا یا اس کے کسی پیغمبر یا کسی بھی برگزیدہ ہستی کی توہین وتنقیص پر مبنی یا اس کو مستلزم ہونا ایک بات ہے اور باقاعدہ توہین کی نیت سے اور خدا یا اس کے رسول یا کسی بھی معتبر شخصیت کے معتقدین کے جذبات کو مجروح کرنے کے ارادے سے ایسا کوئی فعل انجام دینا دوسری بات۔ دنیا میں مذہبی عقیدوں کا اختلاف بھی موجود ہے اور مذہبی شخصیات سے متعلق مختلف آرا رکھنے والے گروہ بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کے خیالات دوسرے گروہ کے عقیدے کے مطابق توہین وتنقیص کو بھی یقیناًمستلزم ہیں، چنانچہ سیدنا مسیح کو الوہیت کے منصب پر فائز کرنا مسلمانوں کے نزدیک خدا کی شان کے منافی اور اس کی تنقیص کو مستلزم ہے جبکہ سیدنا مسیح سے الوہی صفات کی نفی کر کے انھیں ایک عام انسان تصور کرنا مسیحیوں کے نزدیک سیدنا مسیح کی تنقیص شان کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تصریح فرمائی ہے کہ وہ اس دنیا میں اس نوعیت کے مذہبی اختلافات کو ختم نہیں کرنا چاہتا اور اسی لیے اس نے شرک تک کے وجود کو گوارا فرمایا ہے۔ ہر گروہ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جس عقیدے کو درست سمجھتا ہے، اس کو بیان کرے اور جس عقیدے کو غلط سمجھتا ہے، اس کی تردید کرے اور ہر گروہ دوسرے گروہ کے حق کا احترام کرتے ہوئے اپنے ا س حق کو استعمال کرے، چنانچہ خود مسلمان معاشروں میں یہودی اور مسیحی علما اسلام، قرآن اور پیغمبر خدا پر ایسے اعتراضات کرتے رہے ہیں جس سے ان کے خیال میں ہمارے دین کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علماے اسلام نے ایسے اعتراضات کو مذہبی آزادئ رائے کے تناظر میں دیکھتے ہوئے کبھی اس پر قدغن لگانے کی کوشش نہیں کی بلکہ استدلال کا جواب استدلال ہی کے میدان میں دیا ہے۔
جس چیز کو شریعت میں دنیوی قانون کے اعتبار سے قابل مواخذہ کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ اپنے عقیدے کی وضاحت اور مخالف عقیدے کی تردید کے لیے ناگزیر اسلوب بیان سے تجاوز کر کے ایسا طرز بیان اختیار کرے جس کا مقصد اصلاً تبلیغ نہیں بلکہ توہین وتنقیص ہو اور اس میں مخالف گروہ کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کے بجائے محض اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا مقصود ہو۔ شیعہ حضرات اگر خلفاے ثلاثہ کی خلافت کو مبنی برحق نہیں سمجھتے تو وہ اپنے اعتراضات علمی دلائل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور علماے اہل سنت نے بھی ان کا یہ حق تبلیغ تسلیم کرتے ہوئے دلائل کا جواب دلائل ہی سے دیا ہے۔ اس کے برعکس ان کے واعظین اور ذاکرین جس لب ولہجے اور جس اسلوب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ تبلیغ کے دائرے میں نہیں بلکہ توہین کے دائرے میں آتا ہے اور قانونی طور پر سزا کا محل یہی دائرہ ہے۔ عہد صحابہ میں بھی جن غیر مسلم گروہوں سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا، ان کے ساتھ یہی شرط طے کی گئی کہ وہ ’’مسلمانوں کے سامنے‘‘ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نامناسب انداز میں نہیں کریں گے۔ حاصل یہ کہ کسی ایک گروہ کے عقیدے کا دوسرے گروہ کے عقیدے کی رو سے توہین وتنقیص پر مبنی ہونا الگ مسئلہ ہے اور باقاعدہ توہین وتنقیص کی نیت اور ارادے سے ایسا طرز بیان اختیار کرنا جس سے دوسرے گروہ کے جذبات مجروح ہوں، ایک الگ بات ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ملحوظ رکھا جائے تو میرے خیال میں وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے ذکر کیا ہے۔
جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح عبد اللہ بن ابی پر بھی توہین رسالت کی سزا نافذ نہیں کی تو اس کی وجہ، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی واضح کیا ہے، یہ ہے کہ یہ سزا دراصل ایک تعزیری سزا ہے جس میں جرم کی نوعیت، اس کے اثرات، مجرم کی حیثیت اور اسے سزا دینے سے رونما ہونے والے ممکنہ سیاسی وسماجی اثرات، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت سے مجرموں کو نظر انداز کرنے یا ان سے درگزر کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا جبکہ بہت سے لوگوں پر سزا نافذ کرنے کو قرین مصلحت دیکھتے ہوئے سزا نافذ فرما دی۔ یہ حکمت آج بھی ملحوظ رکھنی چاہیے۔ مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی توہین رسالت کے ہر واقعے سے ایک ہی لگے بندھے قانونی طریقے سے نمٹنے کا پابند ہے اور یہ کہ اس معاملے میں اسلام اور مسلمانوں کی وسیع تر سیاسی اور دعوتی مصلحتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ میرے نزدیک اس معاملے میں فقہاے احناف کا موقف ہی ان بہت سی الجھنوں کا قابل عمل حل پیش کرتا ہے جو آج امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے قانون میں اس جرم پر متبادل سزا کی گنجائش موجود تھی جسے بعد میں ختم کر کے متعین طور پر موت ہی کی سزا کو لازم کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی قانونی غلطی تھی اور جلد یا بدیر ہمیں نہ صرف قانون کی سطح پر احناف کے موقف کو وزن دینا ہوگا بلکہ عام سماجی سطح پر بھی لوگوں کو اس کی حکمت سے روشناس کرانا ہوگا۔
امید ہے کہ یہ گزارشات زیر بحث سوالات کے حوالے سے میرا مدعا واضح کرنے میں مدد دیں گی۔ بصورت دیگر آپ کی طرف سے مزید تنقیحی سوالات کو خوش آمدید کہوں گا۔ بے حد شکریہ!
(۳)
برادرم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ
آپ نے لکھا ہے کہ کسی شخصیت یا عقیدے کی توہین اور اس پر علمی وعقلی تنقید میں فرق کرنا بعض صورتوں میں عملی اعتبار سے پیچیدہ بن جاتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے۔ اپنے عقیدے کی تبلیغ، مخالف عقیدے پر تنقید اور اس کی توہین، ان تینوں میں کچھ چیزیں یقیناًمشترک ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ بات قابل فہم ہے کہ کچھ چیزیں ان کے مابین فارق بھی ہیں۔ چنانچہ کسی مخصوص فعل کے بارے میں یہ طے کرنے کے ضمن میں اختلاف کی گنجائش یقیناًرہے گی کہ وہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے یا توہین کے۔ کسی بھی اخلاقی یا قانونی اصول کے عملی اطلاق میں ایسے اختلاف سے کسی طرح بچا نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے فصل نزاع کے لیے ہر مہذب معاشرہ ایسے معاملات میں فریقین میں سے کسی کو ازخود قضیہ نمٹانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ قانون اور عدالت کی صور ت میں (مفروضہ طور پر) ایک غیر جانب دار ثالث کی طرف رجوع کرنے کا پابند بناتا ہے۔ ضروری نہیں کہ عدالت کا فیصلہ بھی حقیقی طور پر انصاف پر مبنی ہو، تاہم اس دنیا میں اس سے ہٹ کر کوئی تدبیر اختیار کرنا ممکن نہیں اور شریعت یا کوئی بھی قانون دراصل انسانی عقل وتدبیر کی اس نارسائی کو پہلے دن سے مان کر آگے چلتا ہے۔
اسی طرح آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ بعض صورتوں میں ایک گروہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے کسی ایسے اقدام کو بالکل جائز تصور کرتا ہے جو دوسرے گروہ کے نزدیک اس کے مذہب کی توہین شمار ہوتا ہو۔ اس ضمن میں محمود غزنوی کے بجائے زیادہ واضح مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات کی ہے جو آپ نے کعبہ میں موجود بتوں کو توڑ دینے اور جزیرۂ عرب میں ہر جگہ مشرکین کی عبادت گاہوں، بت خانوں اور استھانوں کو منہدم کرنے کے سلسلے میں فرمائے۔ اس صورت میں دراصل دو اخلاقی اصول باہم مزاحم ہوتے ہیں: ایک دوسرے مذہبی گروہوں کی آزادئ رائے کا احترام اور دوسرا حکم الٰہی کی تعمیل اور منشاے خداوندی کی تکمیل۔ کوئی بھی مذہبی گروہ جب کسی اخلاقی اصول کی پابندی قبول کرتا ہے تو محض دوسرے مذہبی گروہوں کے جذبات کی رعایت کی خاطر نہیں بلکہ بنیادی طور پر خود اپنی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں قبول کرتا ہے، چنانچہ جہاں اس کی مذہبی تعلیمات اسے رواداری کا درس دیتی ہیں، وہاں وہ رواداری اختیار کرتا ہے اور جہاں وہ اس سے اس کے برعکس کوئی تقاضا کرتی ہیں، وہاں وہ اس تقاضے کو بجا لاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی بے گناہ انسان کی جان لینا خود شریعت کے حکم کی رو سے حرام ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے کی اور خضر علیہ السلام راہ چلتے ایک بے گناہ لڑکے کی جان لینے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مذہب کے دائرے میں تمام اخلاقی اصولوں میں برتر اصول (overriding principle) کی حیثیت صرف اطاعت کو حاصل ہے۔ ایسی صورت میں جو گروہ receiving end پر ہو، اسے اپنے عقیدے سے دیانت دارانہ وابستگی کا ثبوت دینے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے اور اپنی حکمت کے تحت اس میں اس نوعیت کے بہت سے تضادات رکھے ہیں۔ ہمارے لیے اسے اسی طرح قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
آپ نے لکھا ہے کہ اگر توہین رسالت پر سزا حرابہ اور فساد فی الارض کے اصول کے تحت آتی ہے تو پھر اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں یہ ’حد‘ ہوگی اور اس میں معافی نہیں ہو سکتی۔ میری رائے میں اول تو یہی بات درست نہیں کہ ’حد‘ میں تخفیف یا معافی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی کتاب ’’حدود وتعزیرات‘‘ کے ایک مستقل باب میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں کہ اگر کوئی معقول شرعی حکمت تخفیف یا معافی کا تقاضا کرتی ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ہدایت فرمائی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی لشکر جنگ کے لیے نکلا ہو اور لشکر میں شامل کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ فقہا نے اس کی وجہ ’مفسدہ‘ پیدا ہونے کا اندیشہ بیان کی ہے۔ ابن ابی کا مواخذہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے نہیں کیا کہ ایک تو انصار کے ایک گروہ میں، جن کا وہ سردار تھا، اس سے منفی جذبات پیدا ہوں گے اور دوسرے، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی آیت محاربہ کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ شارع یہاں سزا کے لیے حالات کے لحاظ سے مختلف صورتوں کے انتخاب کو قاضی یا حاکم کی صواب دید پر چھوڑنا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک اسی اسلوب سے یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ ریاست کے خلاف سیاسی نوعیت کے جرائم کا مواخذہ کرتے ہوئے سیاسی ومعاشرتی مصلحتوں اور مواخذہ یا درگزر، دونوں کے نتائج واثرات کے تناسب کو ملحوظ رکھا جائے۔
(۴)
(بعض اہل دانش نے یہ نکتہ اٹھایا کہ بعض روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں توہین رسالت کے ایک عادی مجرم کو قتل کر دینے پر قاتل کو بری کر دیا، حالانکہ وہاں اپنے دفاع کے لیے نہ مقتول موجود تھا اور نہ الزام کی صحت پر کوئی گواہ، جبکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اس کے جواب میں یہ مختصر خط لکھا گیا۔)
مکرمی! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
آپ کے تبصرے کی بابت عرض ہے کہ:
۱۔ کسی روایت پر اگر بنیادی استدلال کا مدار ہو تو اس کو یقیناًفنی صحت کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن تائیدی طور پر پیش کی جانے والی روایات کے لیے یہ ضروری نہیں۔
۲۔ یہ اشکال مذکورہ واقعے کی پوری تفصیلات کے روایت میں بیان نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عقلی وقیاسی طور پر یہ فرض کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ روایت کے مجمل ہونے کی صورت میں اس کے خلا کو علمی وعقلی اصولوں کی روشنی میں بھرنا چاہیے، نہ کہ اسے بالکل ناقابل استدلال قرار دے دینا چاہیے۔
قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت
محمد یونس قاسمی
اس عنوان پر ماہنامہ الشریعہ کے مارچ کے شمارہ میں گرامی قدر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب اور میرے مضامین شائع ہوچکے ہیں۔ حضرت راشدی صاحب کے جواب الجواب کو پڑھ کر کچھ باتیں مزید لکھی جارہی ہیں۔
بندہ نے اپنے مضمون میں جن چیزوں کو ذکر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اہل تشیع اثنا عشری کی قومی وملی تحریکات میں شمولیت بلاجواز ہے، حضرت راشدی صاحب مدظلہ نے میرے پیش کیے گئے نکات پر بحث نہیں فرمائی بلکہ اپنے مؤقف کو مزید مضبوط کرنے کیلئے مزید حوالہ جات پیش فرمائے ہیں اور دور نبوی کی ایک مثال سے استدلال کرتے ہوئے شیعہ کے ساتھ معاشرتی تعلقات کو جواز فراہم کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔سب سے پہلے دور نبوی کی مذکورہ مثال کے متعلق وضاحت ضروری سمجھتا ہوں ۔دور نبوی میں منافق کفار کے ساتھ نص قطعی سے کافر ثابت ہوجانے کے بعدبھی معاشرتی تعلقات برقرار رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، مگر بات صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ اس کے بعد نص قطعی سے ان منافق کفار کے ساتھ ترک مراسم کا حکم بھی نازل ہوا تھا اور سابقہ احکام منسوخ قرار پائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک تعلقات کے احکام نازل ہوجانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کفار کو اخرج فانک منافق کہہ کر مسجد نبوی اور اپنی مبارک ومطہر مجالس سے نکال باہر کیا تھا۔ مجھے تو یہ بڑی حیرت ہورہی ہے کہ حضرت راشدی صاحب مدظلہ جیسی شخصیت بھی منسوخ آیت سے استدلال کررہی ہے۔ حضرت والا! اگر ان آیات سے استدلال درست ہوتا تو پھر بحکم ربانی ان آیات کے منسوخ ہوجانے کاکیا فائدہ؟ میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ اگر اس پوری مثال کو ہم سامنے رکھیں تو صورت حال یہ بنتی ہے کہ دور نبوی میں جب منافقین کے متعلق کفر کا حکم نازل ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان منافقین کو محض کافر سمجھا، پھر جب ترک مراسم کاحکم نازل ہوا تو ان منافق کفار کو اپنی مجالس، مساجد اور مدارس سے نکال باہر کیا۔ ہم بھی یہ استدلال کرسکتے ہیں کہ اہل تشیع اثناعشری جو کہ منافقین مدینہ کے روپ میںآج موجود ہیں، ان کے متعلق بھی پہلے محض کفر کافتویٰ آیا، پھر جب ان کے عقائد مزید واضح ہوئے توکفر کی خاص قسم ارتداد وزندقہ کافتویٰ آیا جس کے معنی دوسرے لفظوں میں ترک تعلقات ہی تھے۔ پھر ان پر حضرات نے مزید تحقیق کی تو ان سے کھلم کھلا اعلان برأت کرنے اور ہر طرح کے تعلقات توڑنے اور انہیں اپنے سے دور کرنے کا فتویٰ آیا۔ لہٰذا جیسے ہم نے ان پر کفر کا فتویٰ مان کر انہیں کافر قرار دیا، بعد میں آنے والے فتاویٰ جات کو بھی مانتے ہوئے ان سے ترک تعلقات کرنے چاہییں۔دور نبوی کی مثال بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے۔
جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ مختلف تحاریک میں شامل رہے ہیں تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان کے متعلق پہلے محض کافر ہونے کا فتویٰ تھا، اس لیے ان کے ساتھ عام کفار جیسا برتاؤ کیا جاتا رہا۔ پھر ہمارے بعض اکابر نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان پر تحقیق کی۔ مجھے اس سلسلہ کی سب سے پہلی تحقیق ۱۳۴۸ھ میں علامہ عبد الشکور لکھنوی فاروقیؒ کی نظر آتی ہے۔ حضرت لکھنویؒ نے اپنی تحقیق کو ان الفاظ کے ساتھ اہل علم کی خدمت میں پیش کیا: ’’اہل سنت والجماعت بوجہ ناواقفیت کے شیعوں کومسلمان سمجھ کران کے ساتھ مناکحت تک سے پرہیز نہیں کرتے، بالآخر جس کے تلخ ترین نتائج سوہان روح ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مسلمان شیعوں کو مسلمان سمجھ کر ان کا ذبیحہ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔‘‘ پھر اپنے فتویٰ میں رقم طراز ہیں: ’’شیعوں سے مناکحت ناجائز اور ان کا ذبیحہ حرام اور ان کا چندہ ناجائز اور ان کا جنازہ پڑھنا یا ان کو اپنے جنازوں میں شریک کرنا شرعاً قطعاً ناجائز ہے۔ سنی جنازہ میں یہ لوگ میت کے لیے بددعا کرتے ہیں، کمافی کتبہم‘‘ (بحوالہ۔شیعہ اثنا عشریہ کے کفرو ارتداد کے متعلق علماء کرام کا متفقہ فتویٰ، صفحہ ۳)
حضرت لکھنویؒ نے اپنے اس فتویٰ کو اکابر دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں پیش کیاتاکہ وہ حضرات اس کی تائید اور تصدیق فرماسکیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی ؒ کے خلیفہ اجل ،رئیس المناظرین ،دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تعلیمات کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد مرتضی حسن چاند پوریؒ اسی فتویٰ پر اپنے تائیدی وتصدیقی دستخط ثبت فرمانے سے پہلے یہ الفاظ تحریر فرماتے ہیں: ’’روافض صرف مرتد ،کافر اور خارج ازاسلام ہی نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بھی اس درجہ کے ہیں کہ دوسرے فرق کم نکلیں گے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے جمیع مراسم اسلامیہ ترک کرنا چاہییں۔‘‘ اکابر دارالعلوم دیوبند میں سے جن حضرات نے اس فتویٰ کی تصدیق وتائید کی، ان میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ ، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانیؒ ، مدرس دارالعلوم دیوبند شامل ہیں۔ (بحوالہ شیعہ اثنا عشریہ کے کفرو ارتداد کے متعلق علماء کرام کا متفقہ فتویٰ،صفحہ۶،۷)
۱۳۴۸ھ کا یہ فتویٰ شاید میرے مخدوم محترم حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ کی نظروں سے نہیں گزرا، کیونکہ اگر حضرت نے اس فتویٰ کو ملاحظہ فرمایا ہوتا تو یقینااپنی صفوں میں اس گروہ باطل کی شمولیت کو جواز فراہم کرنے کے لیے مضمون نہ لکھتے بلکہ ان کے خلاف نبرد آزماشخصیات کے دست وبازوبنتے۔اس فتویٰ کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نائب مفتی،فقیہ امت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے جانشین وفرزند ارجمندحضرت مولانا مفتی مسعود احمدؒ کی تحریر’’شیعہ اثنا عشریہ کے کفرو ارتداد کے متعلق علماء کرام کا متفقہ فتویٰ‘‘ کے صفحہ نمبر۸،۹ پر انتہائی قابل دید ہے جسے میں یہاں ذکر نہیں کررہا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ موجودہ دور کے اکابر علماء امت کے سامنے اس انداز میں بحث وتکرار کر سکوں، البتہ اس کی ایک کاپی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ کی خدمت میں ارسال کررہا ہوں تاکہ اگر یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے تو وہ ملاحظہ فرمالیں اور دیگر حضرات میں سے جس کسی نے ملاحظہ کرنی ہو، وہ حضرت راشدی صاحب سے رابطہ کرلیں۔
اہل تشیع اثنا عشریہ سے ترک تعلقات کے متعلق دوسرا فتویٰ موجودہ دور کے اکابر علماء امت کا ہے جس کاتذکرہ ماہنامہ الشریعہ کے گذشتہ شمارے میں شائع ہونے والے میرے مضمون میں ہوچکا ہے۔ابھی حال ہی میں محقق اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہیدؒ کی اس تحقیق و فتویٰ کی تصدیق دارالعلوم دیوبند کے موجودہ رئیس الافتاء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی مدظلہ اور دیگر مفتیان عظام نے بھی کردی ہے۔حضرت مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی نے اس فتویٰ پر جو الفاظ تحریر فرمائے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں’’تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ جواب بالکل صحیح ہے۔شیعہ کے جو عقائد ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ اپنے عقائد باطلہ کی بنیاد پر کافر ومرتد ہیں۔ان سے مذکورہ بالا تعلقات اور مراسم اسلامیہ رکھنا جائز نہیں۔‘‘
آخر میں محسن اہل سنت ،حضرت مولانا محمد منظور احمد نعمانیؒ کے ایک خط کا چھوٹا ساپیرا گراف بھی شامل کررہا ہوں جو انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ کے نام لکھا تھا۔ اس خط کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اکابر کی شدت جذبات کا احساس ہو اور یہ اندازہ ہوکہ خود ہم اکابر پر کتنا اعتماد کررہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دانستہ یا نادانستہ اپنے اکابرامت کے فیصلوں کا مذاق اڑارہے ہیں۔
’’پاکستان میں کے بعض قابل اعتماد حضرات نے مجھے لکھا ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ارکان میں بعض معروف شیعہ علماء ومجتہدین ہیں اور وہ برابر جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اسی حیثیت سے ان کے نام شائع ہوتے ہیں،یہ ان کے مسلمان بلکہ خواص مسلمین اور محافظین اسلام ہونے کا ثبوت ہے۔ نہ صرف خدا کرے یہ اطلاع غلط ہولیکن اگر خدانخواستہ یہ اطلاع صحیح ہے تو میں آپ سے اور آپ کے ذریعے مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت صدر اور دیگر مسلمان اراکین سے عرض کروں گا کہ جلد سے جلد اس غلطی کی اصلاح فرمائی جائے۔ موجودہ صورتحال میں عام مسلمانوں کو یہ بتلانا ہمارا فرض ہے کہ اثنا عشری مذہب اسلام کی شاخ نہیں ہے بلکہ ایک متوازی دین ہے جس کی بنیاد اسلام کی تخریب ہی کے لیے رکھی گئی ہے۔’’الفرقان ‘‘کے مئی، جون، جولائی اور اگست۸۵ء کے شماروں میں، میں نے اس سلسلہ میں جولکھا ہے، وہ نظروں سے نہ گزرا ہوتو ضرور ملاحظہ فرمالیا جائے۔میرے اس عریضہ کی نقل یا فوٹو کاپی کراکر مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت صدر محترم کو بھیج دی جائے اور جناب سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو خود جناب اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام بہتر طریقے سے لے لے،اور اس سلسلے کی کاوش وجدوجہد کو آپ اپنے قرب ورضا کا وسیلہ بنائے۔‘‘ (بحوالہ،ماہنامہ بینات جمادی الاولیٰ۱۴۱۸ھ)
میں نے اپنے گذشتہ مضمون میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ حضرات اکابر علماء کرام کو مل بیٹھ کر اہل تشیع اثناعشری کی قومی وملی تحریکات میں شمولیت کے متعلق علمی بحث ومباحثہ کے بعد متفقہ لائحہ عمل اور ضابطہ اخلاق تیا ر کرنا چاہیے،تاکہ اس عنوان پر جن لوگوں کے تحفظات ہیں، وہ دور ہوسکیں اور ہماری تمام تحریکات مکمل یکسوئی اور اتحاد واتفاق کے ساتھ اپنی جدوجہد میں مصروف رہیں ،یوں ہم نتائج بھی بہترین حاصل کرسکتے ہیں۔اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق اسلام کا سچا سپاہی بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مکاتیب
ادارہ
(۱)
محترم جناب مولانا محمد عمار صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مزاجِ گرامی
کل ہی الشریعۃ کا ڈاکٹر محمود احمد غازی نمبر اور آپ کا رسالہ مسئلہ توہین رسالت موصول ہوئے۔ توقع نہیں تھی کہ اتنے مختصر وقت میں اتنی ضخامت کا نمبر تیار ہوسکے گا۔ غازی صاحب رحمہ اللہ پر خصوصی نمبر شائع کرنے میں شرفِ سبقت غالباً آپ ہی کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو مقبول اور نافع بنائیں۔ آمین۔ الحمد للہ ڈاکٹر کی حیات وخدمات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑگئی ہے۔ میری نظر میں غازی صاحب جیسی شخصیات کے کردار کا پہلو نمایاں کرنا ان کی علمی خدمات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ایک تو اس لیے کہ کسی کے علمی کام پر کوئی بھی کسی بھی وقت کام کرسکتا ہے ، جبکہ کسی کے کردار وعمل پر چند لوگ ہی روشنی ڈال سکتے ہوتے ہیں۔ دوسرے اس لیے کہ آج کے دور میں میرے جیسے بے عمل لوگ جن پر کچھ لفظ جاننے کی تہمت لگی ہوئی ہو، ان کو اس طرح کے نمونوں کی غالباً زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
توہین رسالت کے مسئلے آپ کی تحریر جب ای میل کے ذریعے موصول ہوئی تھی، اس وقت اس کا سرسری مطالعہ کیا تھا، اب مطبوعہ کتابچے میں غالباً اس پر کافی اضافات ہیں۔ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اس پر لکھنے کی بہر حال ضرورت تھی، اس لیے کہ بہت سے ایسے پہلوؤں کو اجماعی اور ناقابل بحث بناکر پیش کیا جارہاہے جو نہ صرف مختلف فیہ ہیں بلکہ فقہ حنفی کے بھی معروف نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ اس حقیقت کو وہ لوگ بھی نظر انداز کررہے ہیں جن کے دن رات در مختار اور شامی کے ساتھ گذرتے ہیں۔ ایک ہی نقطہ نظر کو اس شد و مد کے ساتھ بیان کیا جارہاہے کہ بادی النظر میں یہ محسوس ہوتاہے کہ فقہ حنفی نے اس مسئلے میں اس ایمانی حمیت کا ثبوت نہیں دیا جو ضروری تھی، جبکہ مجموعی طور پر حنفی نقطہ نظر بھی دلیل کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع پر مفصل کام کی ضرورت کا عرصے سے احساس ہو رہا تھا۔ آپ کی اس تحریر سے کافی حد تک یہ ضرورت پوری ہوگئی ہے۔ بعض جگہ اندازِ استدلال یا کسی خاص دلیل سے اختلاف تو ہوسکتاہے، لیکن مجموعی طور پر آپ کے نتائجِ بحث درست معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے علامہ ابن تیمیہ یا جمہور کے دلائل کے حوالے سے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے زیادہ تر مستدلات فعلی یا تقریری احادیث ہیں، قولی اور تشریع عام کی حیثیت رکھنے والی حدیثیں نہیں ہیں۔ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر حجت ہے، لیکن ان سے استدلال کے انداز میں ہمیشہ فقہا نے فرق کیاہے۔ میرے خیال یہ نکتہ اگر زیادہ تفصیل سے آجاتا تو شاید مناسب ہوتا۔
تعزیر اور سیاست کے پہلو پر بات کرتے ہوئے آپ نے عموماً قاضی کے اختیارات کا تذکرہ کیا ہے۔ بظاہر جرم کی نوعیت اور مجرم وجرم کے حالات کا بہتر فیصلہ قاضی ہی کرسکتاہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ علامہ شامی نے ’’تنبیہ الولاۃ والحکام‘‘ میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس میں فیصلہ کرنے کا اصل اختیار قاضی کی بجائے امام کو حاصل ہے۔ اس سے اس معاملے میں عدلیہ کے علاوہ دیگر ریاستی اداروں کے کردار کی نشان دہی ہوتی ہے۔
اللہ کرے، آپ کی اس کاوش سے یہ بحث علمی انداز سے آگے بڑھے اور کوئی ایشو کھڑا ہونے کی بجائے اہل علم دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور اس سے مسئلہ منقح ہونے اور موجودہ حالات میں درست لائحہ عمل طے کرنے میں مدد ملے۔
(مولانا مفتی) محمد زاہد
جامعہ اسلامیہ امدادیہ، فیصل آباد
(۲)
محترم مولانا عمار خان ناصر صاحب
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
دلیل جب تک عقل و نظر کی میزان میں نہ تولی جائے، اس وقت تک اس کی قیمت صاحب دلیل کے ہاں تو مسلم ہو سکتی ہے،علم و تحقیق کی دنیا میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ۔ الحمد للہ الشریعہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو کسی تعصب کے بغیر ہر صاحب دلیل کو میزان فراہم کرتا ہے کہ وہ دوسرے نقطۂ نظر اور اس کی دلیل وتنقید کی روشنی میں اپنی دلیل کی قیمت کو جانچ سکے ۔اللہ آپ کو حق و صداقت کی دعوت پر استقامت نصیب فرمائے۔
الشریعہ کے ۲۰۱۰ء کے جنوری،فروری اور مارچ کے شماروں میں’ اسلامی بنکاری :غلط سوال کا غلط جواب ‘کے عنوان سے جناب زاہد صدیق مغل صاحب نے اپنی کچھ معروضات پیش کی تھیں جس کے بعد مئی،جون اور اگست کے شماروں میں مفتی محمد زاہد صاحب نے ’بلاسود بنکاری کا تنقیدی جائزہ(منہج بحث اور زاویہ نگاہ کا مسئلہ ) ‘کے عنوان سے اپنی معروضات پیش کیں جو کہ اصل میں زاہد صدیق صاحب کے اعتراضات کا جواب ہی تھا۔ مغل صاحب نے دوبارہ قلم اٹھایا اور’ اسلامی بنکاری :زاویہ نگاہ کی بحث‘کے عنوان سے مفتی زاہد صاحب کے مضمون پر جون،اگست اور ستمبر کے شماروں میں تفصیلی نقد لکھا۔ امید تھی کہ مفتی صاحب اس پر مزید لکھیں گے کیونکہ مغل صاحب کے مضمون میں کچھ باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں میرا جیسا طالب علم بھی سر سری نگاہ ڈال کر سمجھ جاتا ہے کہ ان میں یا تو واضح طور پر خلطِ مبحث سے کام لیا گیا ہے یا غیر متعلقہ مباحث پر قرطاس وروشنائی کو صرف کیا گیا ہے یا کم از یہ ان باتوں پر مزید لکھا جائے گا۔ لیکن مفتی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جو کہ کسی مصلحت کی بنا پرہی ہوگا،کیونکہ الشریعہ میں چھپنے والے بعض خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات بنکاری سے ذاتیات پر اترتی جا رہی ہے اور یہی بات قرین قیاس لگتی ہے۔
اٹھائے گئے ایشوز پر تفصیلی طور پرتو بلا سود بنکاری سے وابستہ کار ہی لکھ سکتے ہیں، لیکن کم علمی کے باوجود دو تین باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ عریضہ لکھ رہا ہوں۔
پروفیسر زاہد صدیق مغل صاحب نے اپنے مضمون’ اسلامی بنکاری :زاویۃ نگاہ کی بحث‘ اگست کے شمارہ میں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ بلا سود بنکاری کے مجوزین کا مفروضہ (کہ یہ عوام کی ناگزیر ضروت ہے) ہی محل نظر ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سٹیٹ بنک آف پاکستان کی سالانہ رپوٹ کی مدد سے ایک ٹیبل بنا کر یہ تخمینہ پیش کیا ہے کہ آبادی کے تناسب سے 13.7% لوگ اس نظام سے وابستہ ہیں اور پھر مختلف کمپنیوں پراجیکٹس اور ایسے اکاؤنٹ جو بوجہ ضرورت کھلوائے جاتے ہیں، ان کو نکال کر8%تک تسلیم کیا ہے اور اس کو قلیل کہتے ہوئے طنز کے انداز میں لکھتے ہیں کہ ’’سوال یہ ہے کہ کیا آبادی کے اسقدر قلیل افراد کے عمل کو’عوام کی نا گزیر ضرورت‘ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی نوے فی صد سے زیادہ وہ اکثریت جو بنکوں،اسٹاک ایکسچینج اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی زندگی کی نعمت سے محروم ہو چکی ہے؟آخر آبادی کا یہ اکثریتی حصہ بنکوں کے بغیر اپنا معاش کیسے چلا رہی ہے؟آخر اسلامی بنکاروں کو آبادی کی اس قدر ’محدود اقلیت‘کے مسائل(جن کی نوعیت بھی ذیل میں آرہی ہے)حل کرنے کی اتنی فکر کیوں لاحق ہو چلی ہے؟سارے اجتہادات و توجہ کا محورو مرکزیہی محدود اقلیت کیوں ہے‘‘۔ مزید لکھتے ہیں کہ ’’یہ عجیب منطق ہے کہ دس فیصد عوام کو بنکاری سے بچانے کے بجائے اسلامی کا لیبل چسپاں کر کے نوے فیصد کو اس میں شامل ہونے کے لیے اداراتی صف بندی فراہم کر دی جائے،فیاللعجب‘‘
اول تو مفتی زاہد صاحب کے مضمون میں کم ازکم مجھے یہ بات کہیں نہیں ملی کہ اسلامی بنکاری اس لیے جائز ہے کہ بنکاری ایک ناگزیر ضرورت بن گئی ہے۔ مغل صاحب نے خود ایک نظریۂ ضرورت ایجاد کرکے اس کی تردید شروع کردی ہے۔ مفتی صاحب نے پہلی قسط میں بڑی وضاحت سے غیر سودی بنکاری کا پس منظر بیان کیا ہے، اسے دوبارہ ملاحظہ فرمانے کی ضرورت ہے ۔ مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر سودی بینکاری سودی بنکاری کے خلاف علما کی جد وجہد کا ایک فیز ہے اور ان علما کو اس پر اس لیے غور کرنا پڑا کہ دین دار عبادت گذار لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو سود کی وعیدیں سنانے کے باوجود اسے چھوڑ نہیں رہے تھے ۔ اب ان کی خاطر سود کو تو حلال نہیں کہا جاسکتا تھا، البتہ چند مباح عقود کی طرف ان کی راہ نمائی کی جاسکتی تھی ۔
اس بات سے قطع نظر بھی کرلیا جائے تو کیاجناب مغل صاحب سے یہ پوچھنے کی جسارت کی جاسکتی ہے کہ کیا پاکستان جیسے غریب ملک میں ہر آدمی خود کفیل ہے یا ایک آدمی کئی کئی افراد کا بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی لیبر فورس55.77ملین ہے جس کو آبادی پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک صاحب روزگار ایک نہیں بلکہ اوسطاً تقریباً 3.5آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ان میں کتنے بچے ہیں جو اپنی ماں باپ کی انگلی کے سہارے پل رہے ہوتے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے سہارے جی رہی ہوتی ہیں،اور کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے رحم و کرم پر زندگی کے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں ۔ تو کیامغل صاحب کے اعدادو شمار کے مطابق 10% تعداد خود بخود35% نہیں بن جاتی؟ اس کو قلیل کہیں گے یا کثیر؟ حاصل یہ کہ بنکوں میں افراد کے کھاتوں کی تعداد کو ان کے زیرِ کفالت افراد کے ساتھ ضرب دے کر پھر کل آبادی میں سے اس کا تناسب نکالنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دن بدن عام آدمی کا بھی بنک کی طرف رجحان بڑھ رہاہے۔ میرا اپنا تعلق دیہاتی پس منظر سے ہے ، مجھے معلوم ہے کہ عام دیہاتی جو بنک کے قریب سے گذرتا ہوا بھی ڈرتاتھا، اب وہ بھی اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں یہ تناسب بڑھے گا۔ اس لیے مغل صاحب کے استدلال کو اسی طرح لے بھی لیا جائے جس طرح وہ اسے پیش کررہے ہیں، تب بھی اس استدلال کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔
مغل صاحب نے ’’الضرورات تبیح المحظورات‘‘ پر کافی صفحات لکھے ہیں، حالانکہ مفتی صاحب نے کہیں اس اصول کو بنیاد ہی نہیں بنایا۔ پھر بھی مان لیا جائے کہ مجوزین کا استدلال اس مقدمے پر مبنی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتاہے کہ یہ اصول کہاں سے اخذ کرلیا کہ اس اصول کے اطلاق کے لیے کم از کم اتنے فیصد آبادی کا اس کے دائرے میں آنا ضروری ہے۔ اگر مغل صاحب کے بقول 8% کا تناسب ہی لے لیا جائے تو یہ بھی کروڑوں کی تعداد بنتی ہے ، کیا اتنے لوگوں کی ضرورت کے بارے میں شرعی دائرے میں سوچنا گناہ ہے؟ آج سنگین بیماریوں کے علاج کی بعض صورتیں فقہا کے زیرِ غور ہیں، بعض میں جواز وعدمِ جواز میں اختلاف بھی پایا جاتاہے۔سوال یہ ہے کہ ان بیماریوں میں مبتلا افراد کا تناسب کتنا ہے؟ کیا جب تک ان بیماریوں میں مبتلا افراد کا تناسب مغل صاحب کے معیار تک نہیں پہنچتا، تب تک ایسے کسی مسئلے پر غور اور بحث کو روک دینا چاہیے؟ حاصل یہ کہ اول تو یہاں الضرورات تبیح المحظورات کا کم ازکم مفتی زاہد صاحب کے استدلال میں کوئی حوالہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو ضرورت کا تحقق ایک آدمی کے حق میں بھی ہے اوراس پر یہ اصول لاگو ہوگا۔
مفتی صاحب نے جناب مغل صاحب کو کل اور جز کا فلسفہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہما را اتعلیمی نظام باطل کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے اور اس کی بنیادیں ہی غلط ہیں، لیکن اگر کوئی اس نظام تعلیم کا حصہ ہے تو ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے جس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ کل اور جز کی بحث کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں اگست کے شمارے میں اس مثال کو ’منطقی تضاد پر مبنی الزامی‘ کہتے ہوئے جناب مغل صاحب نے کچھ سوال اٹھائے ہیں جن میں بنیادی باتیں دو ہیں۔ پہلی ’’یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر ایک غلط عمل کسی دوسرے غلط عمل کی دلیل کس طرح بن سکتا ہے؟ (منطق میں اسے Fallacy of two wrongs make a rightکہتے ہیں)۔ پہلی بات یہ کہ راقم الحروف کے کسی جدید تعلیمی درسگاہ کا حصہ ہونے سے یہ کہاں ثابت ہواکہ وہ نظام تعلیم درست ہے؟‘‘ میں مغل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مفتی صاحب خود اس کو غلط نہیں سمجھتے جیسا ان کے مضمون سے واضح بھی ہے کہ وہ اس کو غلط کہنے میں تردد کا اظہار کر رہے ہیں تو ان پر الزامی دلیل کیسے قائم کی جا سکتی ہے کہ’ ’زاہد صدیق کے غلط ہوجانے سے غلط نظام درست ہے‘‘۔ دوسری ’’کیا دعویٰ کرنے والے کے قول و فعل کے تضاد سے اس کے دعوے کی منطقی تردید لازم آتی ہے؟ (منطق میں اسے Fallacy of look who is talkingکہتے ہیں)۔ سگریٹ کو برا کہنے والا اگر خود اس کے کش لگائے تو اس سے سگریٹ کے نقصانات غلط ثابت نہیں ہو جاتے۔‘‘ یعنی مغل صاحب خود اس نظام تعلیم کو برا سمجھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے فرمایا: ’’راقم الحروف موجودہ نظام تعلیم کو سرمایہ دارانہ شخصیت کی تعمیر و تشکیل کا نظام سمجھتا ہے اور اپنے طلبہ کو بھی حد الامکان اس کی بنیادی حقیقت اور موجودہ تعلیمی نظام(خصوصا علم معاشیات) کے تضادات سے آگاہی دینے کی کوشش کرتا ہے۔‘‘ مغل صاحب اپنی غلطی کو عملی غلطی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسلامی بنکاروں کا فکر وعمل دونوں ہی غلط بتاتے ہیں: ’’راقم کا مؤقف یہ ہے کہ مجوزین اسلامی بنکاری کی فکر اور عمل دونوں ہی غلط ہیں۔راقم کے غلط عمل کی بنیاد پرمجوزین اپنی غلط فکر کو درست ثابت نہیں کر سکتے‘‘۔ میں اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا بلکہ جناب مغل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جیسا دین و دنیا کا عالم جس کے قول و فعل میں تضاد ہے کہ وہ ایک نظام کے ناقد ہوتے ہوئے بھی اس کے منافع سمیٹ رہاہے توعوام کا کیا حال ہوگا جو بحیثیت امت 90%تو نماز چھوڑے ہوئے ہیں اور بنکوں کے سود کو سود ماننے پر بھی تیار نہیں ہیں اگر۔ مانتے بھی ہیں تو ضرورت کے درجہ میں چھوڑ بھی نہیں سکتے تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس صورت حال میں امام غزالی کا فلسفہ زہدو قناعت کہاں تک اثر کرے یگاجو بظاہر اس فلسفہ کے علمبرداروں کی زندگی میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ پھر جس نظام سے منافع سمیٹے جا رہے ہوں، اس پر نقد کرتے ہوئے آواز کلاس روم کی چار دیواری سے بھی بلند نہ ہو اور جس نظام سے مفاد وابستہ نہ ہو، اس پر نقد کرتے ہوئے کئی کئی اوراق سیاہ کر دیے جائیں۔ ہم جناب مغل صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ موجودہ نظام تعلیم پر جس کا وہ خود حصہ ہیں، کھل کر لکھیں اور اس کی شرعی صورتحال بھی واضح کریں اور پوری شد ومد کے ساتھ بتائیں کہ اس نظام کا کسی بھی طرح حصہ بننا ناجائز ہے۔ جس طرح انہوں نے خود اپنے عمل کی غلطی کو تسلیم کیا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی اس غلطی سے آگاہ فرمائیں، کیونکہ تعلیمی اداروں میں بہت سے اساتذہ اس نظام کو غلط سمجھتے ہوئے ہی اس کا آلہ کار بنے ہوئے ہوں گے، تاکہ ان پر واضح ہو جائے۔ یہ بھی بتائیں کہ کسی کام کو غلط سمجھ کر کرنے والے میں اور غلط کو صحیح سمجھ کر کرنے والے میں بڑا مجرم کون ہے، جب کہ غلط کو صحیح سمجھنے والے کی خطا بھی اجتہادی نوعیت کی ہوکیونکہ اگر بلا سود بنکاری کے مجوزین کی خطا کو جناب مغل صاحب اجتہادی نہ مانیں تو ان کو نیت پر بھی شک کرنے کا کوئی اختیارنہیں ہے۔
جناب مغل بہت شد ومد کے ساتھ یہ فرمارہے ہیں کہ بینک اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کو پوری دنیا کے علما اور مسلمان ماہرین مل کر کبھی اسلام کے مطابق نہیں بناسکتے، اس لیے ہمیں توقع ہے کہ جناب مغل صاحب کا خود کسی بھی بنک سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور وہ یونیورسٹی سے تنخواہ بھی بنک کی بجائے دستی وصول کر کے اسے گھر میں ہی رکھتے ہوں گے ، اس لیے کہ کسی نظریۂ ضرورت کے عنوان سے وہ ’’ فِٹ اِن‘‘ ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ مغل صاحب نے تو موجودہ کرنسی کو بھی جعلی رسید ہونے کی بنا پر برائی قرار دیا ہے تو میرے جیسا طالب علم یہ پوچھنا چاہے گا کہ وہ بازار میں کون سا سکہ لے کر جاتے ہیں؟ میرے خیال میں تو انہیں یہ پیش کش قبول کرلینی چاہیے کہ وہ ایک ماڈرن یونیورسٹی میں تعلیم دینے کی بجائے کسی دور افتاد گاؤں کے مکتب میں خدمات انجام دیں، اس لیے کہ آج بھی بعض دیہاتوں میں اناج کے ذریعے خرید وفروخت ہوتی ہے اور مولوی صاحب کا حق الخدمت بھی اناج کی شکل میں ہوتاہے۔ اسی کے عوض وہ گاؤں کی’ ہٹی‘ سے اشیا ضرورت خریدتاہے۔کیا مغل صاحب کے نقطۂ نظر سے یہ زیادہ آئیڈیل صورتِ حال نہیں ہے؟ ہمارا مقصد خدانخواستہ کوئی طنز و تعریض کرنا نہیں ہے ، بات یہ ہے جناب پروفیسر صاحب اپنے سے اختلاف رکھنے والوں پر جس انداز کی تنقید کرتے ہیں، اس سے ایک سیدھے سادے قاری کے ذہن میں یہ سوالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔
اسلامی بنکاری کے بارے میں کسی کو مانعین کے نقطۂ نظر سے اتفاق ہو توبھی جواز کو اہلِ علم کی ایک علمی رائے تو تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے بہر حال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس قسم کے مسئلے کو اسلامی قحبہ خانوں والی مثال پر قیاس کرنا کس حد تک درست ہے؟ ایسی اخلاقیات سے گری ہوئی مثالوں سے کسی جاہل کو چپ تو کروایا جا سکتا ہے، لیکن جب اس طرح کی مثال علمی حلقوں میں اپنا نقطۂ نظر ثابت کرنے کے لیے دی جائے تو یہ خود ہی اپنا مدعا کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے ۔ اس پر اگر مد مقابل عافیت کی راہ اختیار کرتے ہوئے چپ کر جائے تو یہ بھی ایک مصلحت مفتی صاحب کی طرف سے خاموشی کی سمجھی جا سکتی ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے مضمون میں جو اہم علمی نکات اٹھائے تھے، ان میں سے اکثر پر پروفیسر مغل صاحب نے کچھ فرمانے کی بجائے انہیں تو وعدۂ فردا پر ٹال دیاہے اور غیر متعلقہ مباحث سے صفحات بھر دیے ہیں۔ مثلاً مفتی صاحب نے اس بات کی نشان دہی کی کہ مغل صاحب کے مضمون میں حدیث کی کسی کتاب کا جو اکلوتا حوالہ دیا گیا ہے یعنی موطا امام مالک کی ایک روایت، اس کا ترجمہ ہی انہوں نے غلط کیاہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ پروفیسرصاحب کے مضمون پر یہ بہت سنجیدہ اعتراض تھا ، لیکن مغل صاحب نے نہ تو یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا کیا ہوا ترجمہ ٹھیک ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی بجائے وہ ایک ثانوی بحث میں الجھ گئے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کے اس اثر کا تفصیلی حوالہ کیوں نہیں دیا۔ اسی طرح مغل صاحب کا بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ بینک( اسلامی بینکوں سمیت) قرض کی جعلی رسیدوں کا کاروبار کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے ، نیز اگر رسید جعلی نہ بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ لین دین کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی، اس لیے کہ دین کے ساتھ تعامل ناجائز ہے۔اس پر مفتی صاحب نے تفصیل سے اس غلط فہمی کے اسباب بیان کرتے ہوئے یہ سوال کیا ہے اسلامی بینکوں کے حوالے سے بالتعیین کسی ایسے معاملے کی نشان دہی کی جائے جو جعلی رسید کے زمرے میں آتاہو یا اس میں دَین کا ایسا لین دین پایا جاتاہو جسے فقہانے ناجائز قرار دیاہے۔
پھر مغل صاحب نے کرنسی کو رسید نہ کہنے والوں کو جس طرح آڑے ہاتھوں لیاہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ مغل صاحب کے پردادا شیخ مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اسی جیسے بلکہ اس سے تلخ لہجے میں رسید کہنے والوں پر رد کیاہے ، مثلاً انہوں نے رسید قرار دینے والی رائے ( جیسا کہ مغل صاحب بھی نہ صرف رسید بلکہ جعلی رسید قرار دیتے ہیں)کو گمان فاسد اور نہایت بد تر شک اور ایسی رائے رکھنے والوں کو سفیہ اور واہم قرار دیاہے۔ مجھے امید ہے کہ پروفیسر صاحب نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے رسالہ کفل الفقیہ الفاہم اور کاسر السفیہ الواہم کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا۔ جناب مغل صاحب نے اپنی تلخ نوائی کا ایک مضمون میں جواز یہ پیش کیا ہے کہ جب غلط بات شد ومد سے کی جارہی ہو تو ایسا ہوہی جاتاہے۔ حضرت فاضل بریلوی کی رائے بھی مغل صاحب کے نقطۂ نظر سے نہ صرف غلط بلکہ انتہائی غلط ہے جبکہ اعلیٰ حضرت اسے بہت شد ومد سے پیش کررہے ہیں اور آج بھی فتاویٰ رضویہ کے ضمن میں اس کی عام اشاعت بھی ہورہی ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ جناب پروفیسر مغل صاحب حضرت فاضل بریلوی کی رد میں اپنے اسی لہجے میں کچھ تحریر فرمائیں گے۔
ہمارے نزدیک اسلامی بینکاری کے مانعین اور مجوزین دونوں طرف کے علما اور ان کی آرا قابلِ احترام ہیں، لیکن محترم پروفیسر مغل صاحب سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ وہ اپنے طریقۂ تنقیدپر ضرور نظر ثانی فرمائیں۔
محمد وقاص (بی ایس، اصول دین)
انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد
(۳)
محترمی ومکرمی مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ
السلام وعلیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ
مارچ۲۰۱۱ء کے شمارے میں آنجناب اور حافظ محمد یونس قاسمی صاحب کی گفتگو پڑھنے کو ملی۔ اسی موضوع پر طالب علمانہ باتیں حاضر خدمت ہیں۔ یہ کوئی ایسی معروضات بھی نہیں جو قبل ازیں آنجناب کے علم وسیع میں نہ ہو ں، لیکن درد دل ہے جو بنا اظہارتھمتا نہیں۔ چند گذاشات حاضر خدمت ہیں:
۱)مرزا کادیانی نے بھی حق تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور شیعہ بھی حق تعالیٰ کی شان گستاخی کرتے ہیں اور عقیدہ بدا کے قائل ہیں۔
۲)مرزا کادیانی نے نبوت کا دعوی کیا تو اہل تشیع بھی اپنے بارہ ائمہ میں صفات نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہؒ کی حجۃاللہ البالغہ تو الشریعہ اکادمی کے علما کے لیے سالانہ کورس میں بھی شامل ہے۔ یہی شاہ ولی اللہ ؒ محدث دہلوی اپنی دوسری تصنیف التفہیمات الالہیہ میں شیعہ کے ختم نبوت کے منکر ہونے کا اعلان فرماتے ہیں اور یہ اعلان آنجناب کے لیے بھی قابل حجت ہونا تو چاہیے ۔
۳)کادیانی حضرات اہل بیتؓ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں تو شیعہ بھی اس فعل شنیع میں کادیانیوں کے ہمراہ ہیں بلکہ شیعہ تو کادیانیوں سے قبل ہی اس فعل کے مرتکب تھے او رشیعہ نے صرف ازواج مطہراتؓ ہی کی گستاخی نہیں کی بلکہ سیدنا علیؓ (آثار حیدری)، سیدہ فاطمہؓ (جلاء العیون)، سیدنا حسنین کریمینؓ (اصول کافی، جلاء العیون) کی بھی گستاخی کی ہے۔
۴)کادیانی قرآن مجید کے بجائے ’’تذکرہ‘‘ نامی کتاب کومانتے ہیں تو شیعہ بھی قرآن کریم کے انکاری ہیں۔
۵)کادیانی اگر صحابہؓ کے گستاخ ہیں تو شیعہ بدرجہ اتم اس فعل بد کے مرتکب ہیں بلکہ شیعہ کی پہچان ہی ا س فعل بد سے ہوتی ہے ۔
۶)کادیانی اگر تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام کے گستاخ ہیں تو شیعہ بھی تابعین،تبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاے امت وجملہ اہل اسلام کے گستاخ ہیں۔
آنجناب کے بقول ’’معاشرتی روابط ومعاملات کا ایک مستقل دائرہ ہے‘‘ اور شیعہ کو مذہبی تحریکات میں اپنے شامل کرنا ’’دراصل سیکولر حلقوں کے اس اعتراض یا الزام کا عملی جواب ہے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص، ملک میں اسلام اور شریعت کی حکمرانی کے بارے میں مذہبی مکاتب فکر پوری طرح متفق ہیں اور پاکستان میں نفاذ اسلام فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں، بلکہ متفقہ مسئلہ ہے۔‘‘ آپ کی ان آرا پربصد ادب عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ شیعہ کو کافر سمجھتے ہوئے بھی معاشرتی روابط ومعاملات کے مستقل دائرہ میں رکھ کر دینی تحریکات واجتماعات میں انھیں شامل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر جماعت احمدیہ کو بھی اسی دائرہ میں رکھ کر دینی تحریکات واجتماعات میں شامل فر ما لیں تاکہ آپ کی آواز میں قوت بھی پیدا ہوجائے اور سیکولر طبقہ میں یہ تاثر بھی قائم ہو جائے کہ مذہبی مکاتب فکر پوری طرح متفق ہیں۔ اس طرح آپ کی رائے کے مطابق اسلام، کفر، نفاق کی بحث کے باوجود معاشرتی اور اجتماعی روایات کو الگ الگ دائرے میں رکھا جا سکے گا اور معترضین کا منہ بھی بند ہو جائے گا کہ تمام تر اعتقادی اور فقہی اختلافات کے باوجود پاکستان میں آباد تمام مذہبی مکاتب فکر ایک ہیں۔ بالفرض آپ چناب نگر (ربوہ) والوں کو شامل اتحاد نہ کر سکیں تو لاہوری فرقہ والوں کو تو ضرور شامل اتحاد فرما لیں۔ اگر یہ بھی نہ کرسکیں تو بس اتنا فر ما دیں کہ جو لوگ قرآن کریم کا صریح انکار کریں، جو بارہ افراد میں خصائص نبوت تسلیم کریں،جو سیدنا ابو بکرؓ، سیدنا عمرؓ، سیدنا عثمانؓ، سیدنا معاویہؓ، سیدہ عائشہؓ اور سیدہ حفصہؓ پر ہر نماز کے بعد لعنت کرنے کو دعا کے لیے باعث قبولیت جانیں، ان کے ساتھ اتحاد کیوں؟
احقر آپ سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت خواہ ہے اگر اس تحریر کے کسی حرف سے آنجناب کی دل آزاری ہوئی ہو۔ سپاہ صحابہ والے مسلک اہل سنت والجماعت سے وابستہ جملہ جماعتوں کی دل سے عزت واحترام کرتے ہیں، لیکن جواب میں انہیں خون کے آنسو رلایا جاتا ہے۔ غیر کی جانب سے آئے ہوئے پتھر کو بھی انسان خوشی سے برداشت کرلیتا ہے لیکن جب اپنوں کی جانب سے ایک سخت جملہ یا سخت اور بے جا تنقید سامنے آئے تو کوہ استقامت انسانوں کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ کوئی مبلغ صاحب جو ش مبلغی میں صحابہ کو سب وشتم کرنے والے کو مسلمان ہونے کا سرٹیفیکٹ عنایت کرتے نظر آتے ہیں تو کوئی صاحب انہیں موساد کا ایجنٹ گردانتے نظر آتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اگر کوئی زخم پر مرہم نہیں لگا سکتا تو کیا ضروری ہے کہ وہ مرہم کی جگہ نمک لگائے؟ اگر کوئی آنسو نہیں پونچھ سکتا تو کیا ضروری ہے کہ وہ مزید رلائے؟ اگر کوئی دلاسہ نہیں دے سکتا تو کیا ضروری ہے کہ وہ تنقید کے طمانچے مارے؟ اگر کوئی ساتھ نہیں دے سکتا تو کیا ضروری ہے کہ وہ احساس تنہائی دلائے؟
مولانائے محترم!آخر سپاہ صحابہؓ والوں کے ساتھ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دفاع صحابہ آپ کے نزدیک جرم ہے؟ میں اور کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں! بس انھی بے ترتیب حروف اور لفظوں پر اجازت چاہوں گا۔ اللہ جل شانہ کی باگاہ میں خلوص قلب سے دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کاسایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔
عبد المنان معاویہ
maviya_114@yahoo.com
(۴)
برادرم عبد المنان معاویہ صاحب
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ نے بہت اچھا کیا جو اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر دیا۔ اس میں نہ کوئی حجاب کی بات ہے اور نہ کسی قسم کی معذرت کی ضرورت ہے۔ ہم ’الشریعہ‘ کے فورم پر اسی رجحان کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جذبات وتاثرات کو سینے میں گھٹے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کا اظہار ہونا چاہیے اور ان پر ایک جائز حد تک کھلا مباحثہ بھی ہونا چاہیے۔ اس سے مسائل کی بہت سی تہیں کھلتی ہیں اور اصل حقائق تک رسائی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔
اہل تشیع کے بارے میں میری سابقہ سب گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے خلاف تمام تر فتاویٰ کے باوجود دینی تحریکات میں ان کے ساتھ ہمارے اکابر کا ربط ومعاونت کا تعلق رہا ہے جو ایک ملی ضرورت سمجھا جاتا ہے اور میری رائے میں آئندہ بھی اس ربط ومعاونت کا تسلسل باقی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اجتماعی مصالح بدستور موجود ہیں جن کی وجہ سے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ قادیانیوں کو ان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کے بارے میں بھی معاشرتی سطح پر اپنے روایتی موقف سے ہٹ کر ایک اجتماعی فیصلہ کر چکے ہیں۔ پاکستان بننے سے قبل قادیانیوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ نہیں تھا کہ انھیں ایک غیر مسلم اقلیت کے طو رپر اسلامی ریاست میں رہنے کا حق دیا جائے، بلکہ ہمارا روایتی موقف شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے معروف رسالہ ’’الشہاب‘‘ کی صورت میں واضح تھا کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور قادیانی بھی مجموعی طور پر اسی زمرے میں شمار ہوتے ہیں، مگر علامہ محمد اقبال کی تجویز یہ تھی کہ قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت کے طو رپر اسلامی ریاست میں بطور شہری رہنے کا حق دیا جائے اور قتل مرتد کی بات نہ چھیڑی جائے۔
قیام پاکستان کے بعد تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کرام نے متفقہ طور پر علامہ محمد اقبالؒ کی اس تجویز کو قبو ل کرتے ہوئے قادیانیوں کو ملک میں غیر مسلم اقلیت کا درجہ دے کر بطور اقلیت ان کی جان ومال اور دیگر حقوق ومفادات کے تحفظ کا اعلان کیا تھا، مگر قادیانیوں نے یہ حیثیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب قادیانیوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات میں پیش رفت کی راہ میں خود قادیانی رکاوٹ ہیں۔ اگر وہ غیر مسلم اقلیت کا درجہ قبول کر کے ملت اسلامیہ کے اجتماعی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تو ہم انھیں ایسے تمام معاملات میں شریک کرنے کے پابند ہوں گے جن میں ملک کی دوسری غیر مسلم اقلیتوں کو شریک کیا جاتا ہے اور وہ بھی دوسری اقلیتوں کی طرح قومی معاشرے کا حصہ تصور ہوں گے، جبکہ اہل تشیع کے بارے میں ملت اسلامیہ نے اس قسم کا کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں کیا اور اگر یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے تو اس کا آغاز حرمین شریفین سے کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات دنیا کے کسی بھی منصف مزاج شخص کو ہضم نہیں ہوگی کہ حرمین شریفین میں تو اہل تشیع نماز، روزہ، حج، عمرہ اور دیگر عبادات میں مسلمانوں کے ساتھ بلا روک ٹوک شریک ہوں اور پاکستان میں انھیں غیر مسلم قرار دے کر معاشرے سے الگ کر دیا جائے۔ اس لیے اگر کچھ دوستوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے کام کا اصل میدان یہ ہے کہ حرمین شریفین میں اہل تشیع کو اہل اسلام سے الگ کرایا جائے اور پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ اہل تشیع کے بارے میں بھی اسی طرح کا اجتماعی فیصلہ کریں جیسا فیصلہ وہ قادیانیوں کے بارے میں کر چکے ہیں۔
جہاں تک سپاہ صحابہ کی قیادت، ناموس صحابہ کے شہدا اور سپاہ کے کارکنوں کا تعلق ہے، ہم نے ان کے خلوص وجذبات، شہادتوں اور قربانیوں کا ہمیشہ اعتراف کیا ہے اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی، تعاون بھی کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر مرحلہ پر ان کے طریق کار سے مسلسل اختلاف بھی کیا ہے۔ میں اس موقع پر والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان دوخطوط کا حوالہ دینا چاہوں گا جس میں انھوں نے سپاہ صحابہ کے قائدین اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے طریق کار سے اختلاف کیا تھا اور اصلاح احوال کی طرف توجہ دلائی تھی۔ یہ خطوط ان کی زندگی میں شائع ہو کر تقسیم ہوئے تھے اور ان کی یاد میں شائع ہونے والی ’الشریعہ‘ کی خصوصی اشاعت میں بھی شامل ہیں۔ انھوں نے جہاں سپاہ صحابہ کی قربانیوں کو ان الفاظ میں سراہا ہے کہ:
’’سپاہ صحابہ کے حضرات نے ایران کی طاغوتی طاقت کے بل بوتے پر اور شہ پر چلنے اور ناچنے والی رافضیت کا پاکستان میں جو دروازہ بند کیا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ دینی لحاظ سے فرض کفایہ بھی ہے۔‘‘
وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ:
’’نوجوان جذباتی ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر بہت کچھ ’’کہہ‘‘ اور ’’کر‘‘ جاتے ہیں۔ شدت اور سختی سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے اور نہ طاقت وقوت سے کسی فرد یا نظریہ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ .... اس لیے گزارش ہے کہ نوجوانوں کو قولاً اور فعلاً شدت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ روکیں۔ رافضیوں کے کفر میں تو شک ہی نہیں، مگر در ودیوار پر ’’کافر کافر‘‘ لکھنے اور ’’نعرہ بازی‘‘ سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ عیاں را چہ بیاں‘‘
سپاہ صحابہ کی قیادت اور کارکنوں کی جدوجہد اور قربانیوں کے بارے میں ہمارے جذبات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ ہم ناموس صحابہ کرام کے تحفظ کی جدوجہد کو بھی دینی فریضہ سمجھتے ہیں اور ایسی ہر جدوجہد میں بحمد اللہ تعالیٰ مختلف مراحل میں شریک کار رہے ہیں، لیکن ہر جدوجہد کے کچھ اصولی اور اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں اور حالات زمانہ کے حوالے سے کچھ ناگزیر ضرورتیں، حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں جن سے صرف نظر کرنا درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم سپاہ صحابہ کے حضرات کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنی جدوجہد کے لیے جو موقف اور طریق کار چاہیں، طے کریں اور آزادی کے ساتھ اس پر عمل کریں، لیکن ملک کی اجتماعی دینی قیادت اور دوسری جماعتوں کی قیادتوں کو اپنے موقف اور طریق کار کا پابند کرنا انھیں یرغمال بنانے کی کوشش کے مترادف ہے جس سے بہرحال گریز کیا جانا چاہیے۔ شکریہ!
ابو عمار زاہد الراشدی
(۵)
برادر محترم محمد عمار خان صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ماہنامہ’الشریعہ‘ ایک ایسا پرچہ ہے جس کا انتظار رہتا ہے اور اس انتظار کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلگتے ہوئے دینی واجتماعی مسائل پر ’’سود وزیاں‘‘ سے بالاتر رہتے ہوئے بحث کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے بہت سے حلقے مصلحت، رخصت، خوف یا استدلال کی صلاحیت میں کمی کے باعث ہاتھ لگانے سے گریزاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ وایمان میں رکھے۔ سچی بات ہے کہ آپ کی یہ ادا اگر ایک طرف سچائی کی تلاش میں قدم بڑھانے کی جسارت ہے تو دوسری جانب برملا آگ کے شعلوں کو پکڑنے کی جرات بھی ہے۔ ہرچند کہ یہ حوصلہ ایک جنس نایاب ہے، مگر اسے پانے کے لیے اعتدال اور ہوش مندی کے دامن کو پکڑنے کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے: دعا اور رد عمل سے بچنے کی کوشش۔ ٹوٹی پھوٹی دعا ہم کرتے ہیں اور رد عمل سے بچاؤ کی کوشش آپ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔
مارچ کے شمارے میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کی تینوں تحریریں اعتدال، ایمان اور حق نصیحت پر دال ہیں۔ اب اگر کوئی نشہ ایمان میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ ’’مولانا بات سمجھے ہی نہیں‘‘ تو اس کے بارے میں یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ بھائی! ذرا اپنے ایمان کی خبر لو۔ یہ نشہ ایمان نہیں، نشہ عصبیت ہے۔
پروفیسر محمد مشتاق احمد صاحب (اسلام آباد) سے، حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ ہی کے پرچے سے متعارف ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں تحقیق وجستجو کی شاہراہ پر کامیابی عطا فرمائے۔ بڑے مشکل پہلووں پر بڑی خوب صورتی سے حق تحریر ادا کرتے آئے ہیں اور تازہ مضمون مختصر ہونے کے باوجود غور وفکر پر ابھارتا ہے۔ تاہم میاں انعام الرحمن صاحب کہ جن سے بڑی توقعات ہیں، وہ ماضی کی قیمتی تحریروں کے برعکس اس مرتبہ اپنے طنزیہ اسلوب پر انحصار کے سبب ذرا دب سے گئے ہیں۔ بڑے اہم موضوع پر انھوں نے محنت سے چیزوں کو اخذ کیا ہے اور سلیقے سے پیش بھی کیا ہے، لیکن کم وبیش ہر دوسرے پیراگراف سے پہلے طنز کے تیر کچھ اس شدت سے برسائے ہیں کہ اس سے پرچہ، نفس مضمون اور خود برادرم انعام صاحب متاثر ہوئے ہیں۔ چلیے، کوئی بات نہیں۔ نوجوان ہیں، ایک بار کر لیا، آئندہ اپنے جذبات یا غصے کو طنز میں ضائع کرنے کے بجائے استدلال میں ڈھال دیں گے۔ بہرحال یہ بات دوبارہ عرض کروں گاکہ اس مضمون کے لیے انعام صاحب نے محنت بھی بے پناہ کی ہے اور زاویہ نظر بھی راست راوی سے مرصع ہے جس نے ان کی سلامتی طبع سے متعارف کرایا ہے۔ ان کا یہ جذبہ بہرصورت قیمتی چیز ہے۔
اسی طرح معاصر عزیز ’محدث‘ جسے ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب مرتب کر تے ہیں، دینی چیلنجوں پر تازہ بہ تازہ رہنمائی دینے میں اولیت پاتا ہے۔ آپ کے ہاں اگر متن کے ساتھ مجرد استدلال سے روشنی تلاش کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے تو ’محدث‘ میں کم وبیش قرآن وحدیث کے متن پر کلی انحصار کر کے رہنمائی کا زاویہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں لہریں بہ یک وقت دینی فہم اور معاصر چیلنج کا جواب دینے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس میں خوشی کا مقام یہ ہے کہ دونوں کے مدیر ہم عمر اور نوجوان ہیں۔ ان شاء اللہ مستقبل میں بہتر علمی روایت کو پروان چڑھانے میں مدد فراہم کریں گے۔
(پروفیسر) سلیم منصور خالد
گوجرانوالہ
(۶)
ڈاکٹر محمود احمد غازی کی یاد میں، الشریعہ کی خصوصی اشاعت پر ادارہ، لکھنے والے اور قارئین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خاص طور جناب محمد عمار خان ناصر کی محنت اور یکسوئی قابل داد ہے۔ اس اشاعت کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اور ان کی خدمات کو سامنے لانے کی نہایت کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ دینی علوم پر مہارت کے بعد جدید علوم پر یکساں عبور حاصل کر کے ڈاکٹر صاحب نے اک عالم کو متاثر کیا۔ ان کے رشحاتِ زبان سے مستفید ہونے کے مواقع ان کے خطابات کی صورت میں مہیا ہیں۔ الشریعہ کی خصوصی اشاعت میں ان کا اچھا آئینہ مرتب ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے بخوبی واقف نہیں تھا، اس لیے اشاعت کا بغور مطالعہ کیا۔ یقینی طور پر مجھے اشاعت کی افادیت کو ماننا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب کے دیانت دارانہ طرز عمل کا تذکرہ جس انداز سے ہوا، وہ میرے لیے اور بھی طمانیت کا باعث ہوا۔ دیانت داری ایک بنیادی صفت ہے۔ یہ اہل مذہب ہی نہیں بلکہ مذہب بیزار لوگوں کے ہاں بھی تسلیم شدہ قدر ہے، مگر ہمارے معاشرے میں بہت پیچھے چلی گئی ہے بلکہ نایاب ہو گئی ہے۔ خاص طور پر اونچے مناصب پر فائز ہونے والوں میں تو اس کا گمان بھی مشکل ہے۔ اس پہلو سے ڈاکٹر صاحب کے جس پختہ طرز عمل کا ہر جاننے والے نے ذکر کیا ہے، وہ ان کے کردار کا ایسا جوہر ہے جسے مزید عام کرنے کی واقعی ضرورت ہے۔
ان کے محاضرات کے مطالعے کا کم و بیش ہر پہلو سامنے آیا ہے۔ اس پہلو سے سب سے زیادہ سلیقہ مندانہ پیش کش جناب محمد رشید صاحب کی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب پر خود سے تو کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، مگر ڈاکٹر صاحب کے خطبات سے اقتباسات منتخب کر کیان کو جس ترتیب سے پیش کیا ہے، وہ بڑی خوبصورت اور متاثر کرنے والی ہے۔
اشاعت پر مفصل تبصرے کی اپنی جگہ افادیت ہے، لیکن سردست میں اشاعت میں پائی جانے والی چند الجھنوں کی جانب توجہ دلانے پر اکتفا کروں گا۔ یہ کوشش بھی کروں گا کہ اصل صورت حال کو سامنے لاؤں۔ اس میں مجھے کس قدر کامیابی ہوئی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ قارئین کے ہاتھ میں ہے۔
ڈاکٹر صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں خاصا اختلاف ہے۔ ادارہ نے اشاعت کے صفحہ نمبر ۱۱ پر جو سوانحی خاکہ درج کیا ہے، اس میں مقام کا ذکر نہیں کیا۔ سبوح سید نمائندہ جیو نیوز نے ڈاکٹر صاحب کا مقام پیدائش کراچی تحریر کیا۔ (ملاحظہ ہو ص: ۲۵۱)۔ پیغامات اور تاثرات کے حصے میں شریف فاروق اور طاہر فاروق کی جو تحریر شامل کی گئی ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ’’انہوں نے پاکستان کے ہائی کمیشن نئی دہلی میں آنکھ کھولی۔‘‘ (ص: ۲۶۷) ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب نے کاندھلہ، مظفر نگر (ہندوستان) کو ان کا جائے پیدائش لکھا ہے۔ انہوں نے تاریخ پیدائش بھی ۱۳ ستمبر درج کی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سید منصور آغا کی اطلاع (جدید خبر، اردو روزنامہ نئی دہلی کی اشاعت ۲۸ ستمبر ۲۰۱۰ء) پر انحصار کیا ہے۔ اس صورت حال کی صراحت تو مرحوم کے لواحقین کر سکتے ہیں۔ مقام پیدائش کے بارے میں ابہام کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن دہلی میں کام شروع کیا۔ ۱۹۵۴ء میں پاکستان آئے۔ قیام پاکستان کے سات سال بعد پاکستان آمد کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی پیدائش کو کراچی سے جوڑنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حافظ صفوان محمد چوہان نے ڈاکٹر صاحب کی تاریخ وفات اپنے مضمون میں ۲۴؍ اکتوبر لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کمپوزر کی غلطی ہو۔ مضمون کے سیاق سباق سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب کے بطور جج تقرری کے بارے میں، لکھنے والوں میں کافی الجھاؤ ہے۔ سوانحی خاکے میں شریعت اپیلیٹ بنچ میں ججی کا زمانہ ۱۹۸۸ء تا ۱۹۹۹ء لکھا گیا ہے۔ اس کے بر عکس مولانا محمد صدیق اراکانی (ماہنامہ حق نوائے احتشام کراچی ) کے حوالے سے صفحہ نمبر ۵۸۸ پر لکھا گیا ہے کہ ’’۲۶؍ مارچ ۲۰۱۰ء کو غازی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے اور آخر دم تک اس خدمت میں مصروف رہے۔‘‘ اگر شریعت اپیلیٹ بنچ والی بات درست ہو تو وفاقی شرعی عدالت والی بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ شریعت اپیلیٹ بنچ، سپریم کورٹ کا بنچ ہے۔ سپریم کورٹ کا جج، بعد میں وفاقی عدالت میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہفت روزہ ضرب مومن کے حوالے سے کہا گیا کہ ’’نواز شریف نے اپنے دورِ حکومت میں انہیں وفاقی شرعی عدالت کا جج اپائنٹ کیا۔‘‘ اسی طرح سود سے متعلق فیصلے میں ڈاکٹر صاحب کے کردار کے بارے میں کافی الجھاؤ ہے۔ خصوصی نمبر کے صفحہ نمبر ۵۷ پر مولانا محمد عیسیٰ منصوری صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ’’اس مشہور فیصلے کا بڑا حصہ ڈاکٹر صاحب ہی کا تحریر کردہ ہے‘‘۔ ڈاکٹر سید عزیز الرحمن انچارج ریجنل دعوہ سنٹر کراچی نے لکھا کہ ’’سود کے خلاف سپریم کورٹ کے مشہور اور تاریخ ساز فیصلے میں بھی ڈاکٹر صانب بحیثیت جج شریعت اپیلیٹ بنچ شریک رہے اور اس فیصلے کا بڑا حصہ ڈاکٹر صاحب ہی کا تحریر کردہ تھا۔ اس بنچ میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی بھی شامل تھے۔‘‘ (صفحہ نمبر ۱۹۲، ۱۹۳)۔ اسی طرح کے ابہامات کئی اور مقامات پر بھی موجود ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمن خان کے حوالے سے اشاعت خاص کے صفحہ نمبر ۵۶۸ پر درج ہے کہ ’’میں نے سود کیس چھ ماہ سننے کے بعد جو جج منٹ لکھی، اگر غازی مرحوم کی معاونت نہ ہوتی تو میرے لیے وہ لکھنا ممکن نہ تھا۔‘‘
قانونی جرائد سے صحیح صورت حال کی جستجو سے یہ واضح ہوا کہ جناب محمود احمد غازی کا ۵؍ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو شریعت ایپلیٹ بنچ میں تقرر کیا گیا۔ یہ نواز شریف کا دورِحکومت تھا۔ وفاقی شرعی عدالت نے سود کیس کا فیصلہ ۱۴؍ نومبر ۱۹۹۱ء کو کیا تھا۔ اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے چیئر مین جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن تھے۔ ان کے ساتھ شریک فیصلہ ججوں میں ڈاکٹر فدا محمد خان اور جسٹس عبیداللہ خان تھے۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بنچ میں مختلف اپیلیں دائر کی گئیں۔ ان اپیلوں پر ابھی سماعت نہیں ہوئی تھی کہ وفاق کی جانب سے واپسی اپیل کی درخواست دائر کر دی گئی۔ وفاق کی جانب سے واپسی کی درخواست مسترد ہوئی۔اس کی رپورٹ PLD 2000 SC 770 میں موجود ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کی جانب سے تھی۔ وفاق واپسی اپیل کی درخواست اور ہاؤس بلڈنگ کی جانب سے اپیل کی سماعت میں جناب محمود غازی دیگر ججوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ ہاؤس بلڈنگ کے علاوہ باقی اپیلوں کی سماعت ایک ہی تاریخوں پر ہوئی۔ یہ سماعت فروری ۱۹۹۹ء سے شروع ہوئی اور ۶ جولائی ۱۹۹۹ء تک جاری رہی۔ باقی اپیلوں کے فیصلے کی رپورٹ پی ایل ڈی میں مطبوعہ رپورٹ میں مقدمے کا عنوان محمد اسلم خاکی بنام محمد ہاشم ہے۔ کیس کا فیصلہ ۲۳؍دسمبر ۱۹۹۹ء کو سنایا گیا۔ اس کی رپورٹ PLD 2000 SC 225 پرموجود ہے۔ ہاؤس بلڈنگ والی اپیل کا فیصلہ مولانا محمد تقی عثمانی نے تحریر کیا۔ اس فیصلے میں زیادہ تر دیگر اپیلوں کے فیصلے پر انحصار کیا گیا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، غازی صاحب کا نام ہاؤس بلڈنگ والی اپیل کی سماعت کرنے والے بنچ میں شامل ہے۔ البتہ ایک بات کو میں نہیں سمجھ سکا کہ دیگر اپیلوں کی سماعت اس اپیل کے ساتھ ہی ہوئی، مگر ان کی سماعت کرنے والے بنچ میں جناب غازی صاحب کا نام شامل نہیں۔
بہر حال واضح ہے کہ ان میں سے کسی کیس میں جناب ڈاکٹر محمود غازی نے الگ سے کوئی فیصلہ نہیں لکھا۔ اس طرح یہ کہنا کہ سود کے متعلق فیصلے کا بڑا حصہ ڈاکٹر محمود غازی کا لکھا ہوا ہے، غلط معلوم ہوتا ہے۔ سود سے متعلق شریعت اپیلٹ بنچ کا فیصلہ جناب جسٹس خلیل الرحمن نے لکھا۔ بنچ کے دیگر ارکان میں سے منیر اے شیخ نے فیصلے پر دستخط کیے، البتہ جسٹس وجیہ الدین احمد اور جسٹس محمد تقی عثمانی نے علیحدہ سے تائیدی فیصلے لکھے۔ جسٹس خلیل الرحمن خان نے خصوصی اشاعت میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر غازی نے فیصلہ لکھنے میں ان کی معاونت کی۔ بہر حال اس معاونت کا جسٹس خلیل الرحمن خان نے اپنے فیصلے میں کہیں ذکر نہیں کیا۔ سال ۲۰۰۰ء میں سپریم کورٹ کے ججوں کی پی ایل ڈی اور پی ایل جے میں ڈاکٹر غازی صاحب کا نام درج نہیں۔ اس کی بدیہی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر غازی پرویز مشرف کی سکیورٹی کونسل میں شامل ہو گئے تھے۔ بہر حال ڈاکٹر غازی ۵؍اکتوبر ۱۹۹۸ء سے سال ۱۹۹۹ء کے اواخر تک سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بنچ میں رہے۔ اس طرح ۱۹۸۸ء تا ۱۹۹۹ء تک ان کے شریعت اپیلٹ بنچ میں رہنے کی بات درست نہیں۔
میں نے اپنی تئیں جستجو کر کے صحیح صورت حال متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی صاحب مزید صراحت کریں تو میرے اور قائین کے لیے مفید ہو گی۔
چوہدری محمد یوسف ایڈووکیٹ
تصویر کے بارے میں ہمارا موقف اور پالیسی
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
’الشریعہ‘ کے مارچ کے شمارے میں شائع شدہ مولانا سختی داد خوستی کے مکتوب اور ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی یاد میں خصوصی اشاعت کی ٹائٹل پر ان کی تصویر کے حوالے سے بعض دوستوں نے تصویر کے بارے میں میرا ذاتی موقف دریافت کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ میرا ذاتی رجحان اس مسئلے میں حضرت امام محمدؒ کے اس قول کی طرف ہے جو انھوں نے ’’موطا امام محمد‘‘ میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ:
عن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود انہ دخل علی ابی طلحۃ الانصاری یعودہ فوجد عندہ سہل بن حنیف فدعا ابو طلحۃ انسانا ینزع نمطا تحتہ فقال سہل بن حنیف لم تنزعہ؟ قال لان فیہ تصاویر وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ما قد علمت، قال سہل: اولم یقل: الا ما کان رقما فی ثوب؟ قال بلی ولکنہ اطیب لنفسی۔
قال محمد: وبہذا ناخذ، ماکان فیہ من تصاویر من بساط او فراش یفرش او وسادۃ فلا باس بذلک، انما یکرہ من ذلک فی الستر وما ینصب نصبا وہو قول ابی حنیفۃ وعامۃ فقہاء نا۔
’’حضرت عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تاکہ ان کی عیادت کر سکیں تو وہاں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک شخص کو بلایا تاکہ وہ ان کے نیچے سے بچھونے کو نکال دے۔ حضرت سہل نے پوچھا کہ یہ بچھونا کیوں اپنے نیچے سے نکلوا رہے ہیں؟ ابو طلحہ نے فرمایا، اس لیے کہ اس میں تصاویر ہیں اور ان تصاویر کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ تمھیں معلوم ہے۔ حضرت سہل نے فرمایا کہ کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ’’مگر وہ تصویر جو کپڑے پر نقش ہو‘‘؟ (یعنی ایسی تصویر حرمت مستثنیٰ ہے)۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے، مگر میں اپنے لیے اسی کو پسند کرتا ہوں۔
امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس لیے جو تصویر بستر پر ہو یا چٹائی پر ہو یا تکیہ پر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ پردے پر یا سامنے کھڑی کی جانے والی تصویر مکروہ ہے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ہمارے جمہور فقہا کا موقف بھی یہی ہے۔‘‘
لیکن چونکہ پاکستان کے جمہور علماء احناف کا رجحان تصویر کے مطلقاً عدم جوازکی طرف ہے، اس لیے جمہور کے اس موقف کا احترام کرتے ہوئے ’الشریعہ‘ میں تصویر کی اشاعت کا سلسلہ ہم نے ترک کر رکھا ہے۔ ہماری اس عمومی پالیسی کے خلاف محترم ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی تصویر کی اشاعت جن قارئین کو ناگوار گزری ہے، ہم ان سے معذرت خواہ ہیں۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’برصغیر میں مطالعہ قرآن‘‘ (بعض علماء کی تفسیری کاوشوں کا جائزہ)
ہندوستان کے معروف علمی وتحقیقی جریدے ’’تحقیقات اسلامی‘‘ کے نائب مدیر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کا تعارف اور ان کی فاضلانہ تصنیف ’’نقد فراہی‘‘ پر تبصرہ قارئین چند ماہ قبل انھی صفحات میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ قرآنی علوم ومعارف مصنف کے مطالعہ وتحقیق کا خاص موضوع ہیں اور وہ ایک عرصے سے اپنی تحقیق کے حاصلات علمی مقالات کی صورت میں پیش کرتے آ رہے ہیں۔ زیر نظر کتاب بھی مصنف کے علمی مقالات کا مجموعہ ہے جس میں بیسویں صدی میں برصغیر کے بعض معروف اہل علم کی تفسیری کاوشوں کے مختلف پہلووں کا تجزیاتی اور تنقیدی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔
پہلے مقالے کا عنوان ’’سرسید کی تفسیر القرآن اور مابعد تفاسیر پر اس کے اثرات‘‘ ہے۔ مصنف نے سرسید کی تفسیر قرآن کی تالیف کا فکری پس منظر واضح کیا ہے اور سرسید کے منہج تفسیر پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن اور بائبل کے بیانات کے تقابلی مطالعہ، اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے رد اور غیبیات ومعجزات کی عقلی توجیہ کو اس کی اہم خصوصیات میں شمار کیا ہے۔ مصنف نے یہ دلچسپ حقیقت بیان کی ہے کہ تفسیر قرآن کے ضمن میں ان تینوں پہلووں سے بعد کے مفسرین نے سرسید کے اثرات قبول کیے اور اردو تفاسیر میں نہ صرف قرآن اور بائبل کے تقابلی مطالعہ اور اسلام پر اعتراضات کا رد کرنے کی ریت قائم ہوئی، بلکہ غیبیات اور معجزات کی عقلی توجیہ کے باب میں بھی ’’اس تفسیر کے مابعد تفاسیر پر اثرات مرتب ہوئے اور اہل علم نے اس کے اسلوب اور انداز تحقیق کو اپنایا۔‘‘ (ص ۲۳) مصنف کے خیال میں اس طرز فکر کے بعض مثبت اثرات بھی ہیں، چنانچہ ’’قدیم مفسرین کی عجوبہ پسندی کا یہ حال تھا کہ وہ ایسے واقعات کو بھی جن کی مناسب عقلی توجیہ ممکن ہے، معجزات قرار دیتے تھے۔ ..... معجزات کے سلسلے میں سرسید کا نقطہ نظر تو قبولیت حاصل نہ کر سکا، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ عجوبہ پسندی کی شدت میں کمی آئی اور بعض قرآنی واقعات پر اس حیثیت سے بھی غور ہونے لگا کہ ان کی عقلی توجیہ کر کے انھیں غیر معجزانہ واقعات کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اسے بھی تفسیر سرسید کا ایک قابل لحاظ اثر قرار دیا جا سکتا ہے۔‘‘ (ص ۲۴) اس نکتے کی وضاحت میں مصنف نے متعدد مثالیں بھی نقل کی ہیں۔ سرسید کی تفسیری خدمات کے حوالے سے مصنف کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ بعض پہلووں سے ’’یہ تفسیر سرسید کی مذہبی خدمات میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور یہ ان کا ایک قابل قدر علمی کارنامہ ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جہاں ان کی غلطیوں اور لغزشوں پر بے لاگ تنقید کی جائے، وہیں ان کی وقیع تحقیقات کو سراہا جائے۔‘‘ (ص ۱۱) یہ رائے مصنف کے خالص علمی ذوق اور مذہبی واختلافات وتعصبات سے بالاتر ہو کر متوازن تجزیہ وتنقید کے رجحان کی غمازی کرتی ہے۔
’’بیسویں صدی عیسوی میں علماے ہند کی تفسیری خدمات میں‘‘ کے زیر عنوان دوسرے مقالے میں عربی زبان میں تصنیف کردہ علمی کاوشوں کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا انور شاہ کشمیری کے نام نمایاں ہیں۔ اس مقالے میں زمانہ قدیم کے اہل علم کی بعض تصانیف کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کی طباعت واشاعت بیسویں صدی میں ہوئی۔ بظاہر ان تصانیف کا ذکر مقالے کے دائرے سے متجاوز دکھائی دیتا ہے، تاہم بیسیویں صدی کے اہل علم نے ترجمہ، تحقیق اور تحشیہ کی صورت میں ان تصنیفات پر جو کام کیا، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک حد تک انھیں اس مقالے میں شامل کرنے کا جواز نکل آتا ہے۔
تیسرا مقالہ ’’بیسویں صدی میں حروف مقطعات کے مباحث‘‘ کے عنوان سے ہے۔ اس مقالے کا حاصل یہ ہے کہ حروف مقطعات کے معنی ومفہوم کی تعیین کے ضمن میں امام طبری نے اپنی تفسیر میں جو اقوال نقل کیے ہیں، بعد کے اہل علم اپنی تحقیقات سے ان میں کوئی معتد بہ اضافہ نہیں کر سکے اور یہی صورت حال بیسویں صدی کے مفسریں کے ہاں بھی برقرار ہے۔ اس ضمن میں ایک منفرد رائے مولانا فراہی نے ظاہر کی تھی جس کی رو سے عربی زبان کے حروف چونکہ عبرانی لیے گئے ہیں جو آواز کے ساتھ ساتھ معانی اور اشیا پر بھی دلیل ہوتے تھے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ بعض قرآنی سورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں، وہ اپنے قدیم معانی اور سورتوں کے مضامین کے مابین کسی مناسبت کے لحاظ سے آئے ہوں۔ تاہم اس رجحان کے حوالے سے خود مولانا فراہی کا تبصرہ یہ تھا کہ ’’جب تک تمام حروف کے معنی کی تحقیق ہو کر ہر پہلو سے ان ناموں اور ان سے موسوم سورتوں کی مناسبت واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر ایک نظریہ سے زیادہ اعتماد کر لینا صحیح نہیں ہوگا۔‘‘ (ص ۶۳) ہمارے علم کی حد تک ابھی تک اس باب میں مولانا فراہی کی ذکر کردہ مثالوں پر کوئی اضافہ سامنے نہیں آیا۔
’’مولانا سید سلیمان ندوی اور مفردات قرآنی کی لغوی تحقیق‘‘ کے عنوان سے ایک مضمون میں قرآنی الفاظ، اعلام اور اصطلاحات کی لغوی وتاریخی تحقیق کے ضمن میں سید سلیمان ندوی کے منہج کی وضاحت مثالوں کی مدد سے کی گئی ہے اور اس تحقیق میں سید صاحب کے علمی مآخذ کی نشان دہی کی گئی ہے۔ یہ مضمون علمی لحاظ سے دلچسپ اور اہم لیکن کافی مختصر ہے۔
’’تفسیر تدبر قرآن میں کلام عرب سے استشہاد‘‘ کے زیر عنوان مقالہ علمی اعتبار سے خاصے کی چیز ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ’’تفسیر قرآن میں کلام عرب ایک اہم ماخذ ہے۔ تمام قدیم مفسرین نے اس سے استفادہ کیا ہے، لیکن متاخرین کے یہاں اس سے استشہاد میں کمی آ گئی تھی۔ مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا امین احسن اصلاحیؒ کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اس کی اہمیت واضح کی اور اپنی تفسیروں میں اس سے بھرپور استفادہ کیا۔‘‘ (ص ۱۱۴) مقالے میں مصنف نے تدبر قرآن میں کلام عرب سے استشہاد کی نوعیت کے مختلف پہلو اور اس ضمن کی بعض اہم اور نمائندہ مثالیں بھی توضیح کے لیے نقل کر دی ہیں۔ صرف ایک مثال ملاحظہ ہو۔ ’ولقد یسرنا القرآن للذکر‘ کا مفہوم واضح کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں:
’’لفظ ’تیسیر‘ عربی میں کسی چیز کو کیل کانٹے سے لیس کرنے، پیش نظر مقصد کے لیے اس کو اچھی طرح موزوں بنانے اور جملہ لوازم سے آراستہ وپیراستہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً یسر الفرس للرکوب کے معنی ہوں گے، گھوڑے کو تربیت دے کر، اس کو کھلا پلا کر، زین لگام رکاب سے آراستہ کر کے سواری کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ یہیں سے یہ لفظ کسی شخص کو کسی مہم کے لیے تیار اور جملہ لوازم سے مسلح کر کے اس کو اس کا اہل بنا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک جاہلی شاعر کہتا ہے:
ونعین فاعلنا اذا ما نابہ
حتی نیسرہ لفعل السید
’’اور جب ہمارے سربراہ کار کو کوئی مہم پیش آتی ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ سرداروں کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی راہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔‘‘ (ص ۹۳)
مصنف نے ناقدانہ نگاہ سے جائزہ لیتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ تدبر قرآن میں اشعار کی تخریج نہیں کی گئی، نیز بعض مقامات پر موزوں اشعار سے استشہاد کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ بعض جگہ مولانا نے کسی قرآنی کلمہ کا مفہوم واضح کرنے کے لیے کلام عرب سے نظائر پیش کیے ہیں، حالانکہ اس مفہوم کے نظائر خود قرآن میں موجود ہیں جن کی طرف مولانا کی نگاہ نہیں گئی۔
اس مقالے کے آخر میں فاضل مصنف نے تفسیر کے مآخذ کے ضمن میں مولانا کی تقسیم سے اختلاف کیا ہے۔ مولانا نے عربی زبان اور کلام عرب کو تفسیر کے قطعی مآخذ میں جبکہ احادیث اور آثار صحابہ کو ظنی مآخذ میں شمار کیا ہے۔ مصنف کی تنقیدیہ ہے کہ ’’دیگر اصولوں کے ساتھ مل کر کلام عرب سے استدلال کے اصول کو کیوں قطعیت مل جائے گی اور احادیث اور آثار صحابہ کو انھی اصولوں کے ساتھ مل کر ویسی قطعیت کیوں نہیں مل سکتی؟ ..... تفسیر قرآن میں احادیث اور آثار صحابہ کو کلام عرب سے کم تر حیثیت دینا صحیح نہیں۔‘‘ (ص ۱۱۳) تفسیر کے ماخذ کی تقسیم اگر قطعیت اور ظنیت کے عنوان سے کی جائے تو اس پر یہ اعتراض ایک حد تک بجا ہے، لیکن اگر اس سے ذرا ہٹ کر غور کیا جائے تو مولانا کے بنیادی زاویہ نگاہ میں بے حد وزن دکھائی دیتا ہے۔ مولانا نے تفسیری وسائل کی یہ تقسیم اصلاً متکلم کے مدعا ومنشا تک رسائی کے لحاظ سے کی ہے۔ کلام کا مفہوم سمجھنے کے لیے جن وسائل سے مدد لی جاتی ہے، ان میں سے کچھ خود کلام کا حصہ ہوتے ہیں اور کچھ اس سے الگ، خارج میں پڑے ہوتے ہیں۔ زبان او رمحاورات کا علم، سیاق وسباق پر غور اور نظائر کا تتبع فہم کلام کے داخلی، جبکہ احادیث وآثار خارجی وسائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ وتابعین سے جو تفسیری روایات منقول ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بذات خود فہم کلام کے داخلی وسائل کو استعمال کرنے کا نتیجہ ہیں، کیونکہ اگر متکلم نے اپنے مدعا کے ابلاغ کے لیے کلا م کو ذریعہ بنایا ہے تو پھر کلام ہی اس باب میں اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے جب متکلم کے مدعا تک رسائی میں مدد دینے والے علمی وسائل کی درجہ بندی کی جائے گی تو فطری طور پر کلام کے داخلی وسائل ترتیب میں پہلے نمبر پر اور خارجی وسائل دوسرے نمبر پر آئیں گے۔ اس لحاظ سے زیادہ درست اور سادہ تقسیم یہ بنتی ہے کہ تفسیر کے مآخذ کو داخلی اور خارجی میں تقسیم کر کے قطعی اور ظنی کو ان دونوں کی ذیلی تقسیمات کے طور پر بیان کیا جائے۔
’’مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ ؒ کی قرآن فہمی‘‘ کے زیرعنوان مقالے میں مصنف بتاتے ہیں کہ اگرچہ مولانا علی میاں کی عام پہچان ایک مورخ اور سوانح نگار کی ہے، لیکن ان قرآن فہمی کا ذوق بھی بہت بلند پایہ ہے اور ان کی تقریروں اور تحریروں، سب کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ اس مقالے میں مولانا کے قرآنی افادات کا تعارف پیش کیا گیا اور قرآن مجید پر غور وفکر سے متعلق ان کے منہج اور اسلوب کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مصنف نے ’فساد فی الارض‘ کی تشریح میں مولانا کی ایک راے نقل کر کے، جس کی رو سے یہ تعبیر صرف اخلاقی بگاڑ تک محدود ہو جاتی ہے اس پر بجا طور پر تنقید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ مفسرین نے اس کی وسعت وجامعیت میں کفر وشرک اور تمام معاصی کو شامل کیا ہے۔ (ص ۱۴۲) اسی باب کے اگلے دو مقالوں میں مولانا صدر الدین اصلاحی کی تفسیر ’’تیسیر القرآن‘‘ (نامکمل وغیر مطبوع) اور ’’تلخیص تفہیم القرآن‘‘ کے اہم خصائص اور علمی نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان دونوں تفسیری کاوشوں میں ایک مشترک نکتہ یہ ہے کہ ان میں قرآنی آیات کی تشریح وتوضیح کرتے ہوئے غیر مسلم ذہن کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ فاضل مصنف کا تاثر یہ ہے کہ تفسیر تیسیر القرآن ’’اپنے اندروں میں بہت سے جواہر پارے سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے اپنی موجودہ ناتمام صورت میں بھی اس کی اشاعت ایک اہم علمی خدمت ہوگی۔‘‘ (ص ۱۷۳)
چوتھا باب ’’قرآنی موضوعات پر چند تصانیف کا جائزہ‘‘ کے عنوان سے ہے اور اس میں متعلقہ موضوع پر ۳۲ تصانیف کا تعارف اور ان پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ’’برصغیر میں مطالعہ قرآن‘‘ (فکر ونظر اسلام آباد کی خصوصی اشاعت)، ’‘تدبر قرآن پر ایک نظر‘‘ از مولانا جلیل احسن ندویؒ ، ’’ذبیح کون؟ اسحاق یا اسماعیل؟‘‘ از عبد الستار غوری، ’’قاموس الفاظ واصطلاحات قرآن‘‘ (افادات: مولانا امین احسن اصلاحی)، ’’قرآن کریم میں نظم ومناسبت‘‘ از ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی اور شش ماہی علوم القرآن علی گڑھ کا مولانا امین احسن اصلاحی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ مولانا جلیل احسن ندوی کی تالیف ’’تدبر قرآن پر ایک نظر‘‘ میں مولانا اصلاحی کی بعض تفسیری آرا پر نقد وتبصرہ کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے المورد، لاہور میں منعقد ہونے والی ہفتہ وار علمی نشستوں میں اس کتاب کے مباحث کا اجتماعی مطالعہ کیا گیا تھا۔ اگر ان نشستوں کی ریکارڈنگ محفوظ ہو اور انھیں مرتب ومدون کر کے منظر عام پر لایا جا سکے تو قرآنیات کے طلبہ کے لیے وہ ایک مفید چیز ہوگی۔ کتاب کا یہ باب غالباً مختلف رسائل وجرائد میں لکھے جانے والے تبصروں کا مجموعہ ہے، تاہم اختصار کے باوجود یہ تبصرے علمی طور پر مفید اور معلومات افزا ہیں۔
فاضل مصنف کی دوسری نگارشات کی طرح زیر نظر مجموعے میں شامل تحریریں بھی بلند پایہ علمی مواد سے بھرپور ہیں اور قرآنی علوم وتحقیقات کے ساتھ مصنف کی گہری ذوقی مناسبت کا پتہ دیتی ہیں۔
کتاب میں شامل مقالات اور خاص طور پر آخری باب میں تبصرے کے لیے منتخب کردہ کتب پر ایک نظر ڈالنے یہ دلچسپ نکتہ سامنے آتا ہے جس کی طرف دینی علوم کے طلبہ کو متوجہ کرنا یہاں برمحل دکھائی دیتا ہے۔ وہ یہ کہ بیسویں صدی میں برصغیر میں ترجمہ وتفسیر کے انداز میں قرآن مجید کی خدمت تو اپنے اپنے انداز میں یقیناًسبھی مکاتب فکر نے کی ہے، لیکن قرآنی علوم اور تحقیقات کے دائرے میں علمی روایت کی تجدید اور اس دائرے میں نئے نئے پہلووں اور مباحث کے اضافے کا کام بنیادی طور پر ان علمی حلقوں کی طرف سے انجام پایا ہے جن کے لیے بعض اہل علم نے مجموعی طور پر ’’دبستان شبلی‘‘ کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اس ضمن میں ماضی قریب کے بڑے ناموں میں مولانا فراہی، مولانا آزاد، سید سلیمان ندوی، عبد الماجد دریابادی، مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کا ذکر کیا جا سکتا ہے جبکہ حالیہ تحقیقات میں بھی ندوۃ العلماء اور مدرسۃ الاصلاح وغیرہ کے فیض یافتگان ہی کا نام نمایاں ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیوی علوم وفنون کی طرح دینی علوم ومعارف کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقسیم کی ہے کہ کوئی بھی حلقہ فکر دوسرے حلقہ ہاے فکر کی علمی وفکری کاوشوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا اور تمام حلقہ ہاے فکر کی مساعی کو امت کی مجموعی علمی میراث کا حصہ سمجھتے ہوئے سب کی قدر دانی اور اعتراف اور کسی تعصب کے بغیر سب سے اخذ واستفادہ ہی صحیح علمی رویہ ہے۔
کتاب کی کتابت وطباعت، کاغذ اور پیش کش کا معیار عمدہ اور کتاب کی علمی سطح کے شایان شان ہے۔ البتہ ٹائٹل کے آخری صفحے پر ناشر کی طرف سے ’’ہماری چند خوب صورت اور معیاری مطبوعات‘‘ کا عنوان دے کر ان مقالات کی ایک فہرست دے دی گئی ہے جو زیر نظر کتاب میں شامل ہیں۔ یوں بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ تمام عنوانات مستقل تصانیف کے ہیں۔ اسی طرح کتابت کی بعض غلطیاں بھی ذوق سلیم کو ناگوار گزرتی ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی اصلاح کر لی جائے گی۔
اس مجموعے کو اسلامک بک فاؤنڈیشن، نئی دہلی نے شائع کیا ہے اور اس کی قیمت ۱۶۰ روپے (ہندوستانی) درج ہے۔ پاکستان میں غالباً یہ سجاد الٰہی صاحب کے پاس دستیاب ہوگی جو ہندوستان سے رسائل وجرائد مطبوعات منگوا کر اہل علم کو فراہم کرنے کا خا ص ذوق رکھتے ہیں۔ (رابطہ: 0300-4682752)
(تبصرہ: محمد عمار خان ناصر)
Islamism and Democracy in India
The Transformation of Jamaat -e-Islami
(ہندوستان میں اسلام پسندی اور جمہوریت: جماعت اسلامی کی قلب ماہیت)
مصنف :عرفان احمد۔ صفحات :306۔ قیمت:695
ناشر: Permanent Black,'Himalayana,Mall road, Rani
Khet Cantt. Rani Khet' (India) 263645
اسلام کا سیاست مرکزی تصور اسلامی نظام کے قیام کواسلامی عقیدے اور عمل کا بنیادی پہلو قرار دیتا ہے اوراس کے مقابلے میں جمہوریت اور سیکولرزم کے تصورات کومسترد کردیتا ہے۔ پچھلی تقریبا نصف صدی سے علمی و سیاسی حلقوں میں اس پر بحث ومباحثہ جاری ہے۔نائن الیون کے بعد اس پر بحث میں تیزی آئی اور یہ اور اس سے متعلق موضوعات پر مختلف زبانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئیں جو شاید گزشتہ کئی دہائیوں میں نہ لکھی گئی ہوں ۔ عالم اسلام کے علماو اہل دانش اورعوام کی اکثریت نے اس نظریے کو کبھی قبول نہیں کیا،وہ ہمیشہ اس کے خلاف رہی۔اس لیے یہ نظریہ اسلامی فکر کے بنیادی دھارے میں شامل نہیں ہوسکا۔تاہم اس وقت اسلام کو سیاسی tool کے طور پر استعمال کرنے والے اسلام پسند تمام اسلامی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سی انقلابی اسلامی تحریکات اپنے مقصد اور فکری اساس کے اعتبار سے یہی تصور رکھتی ہیں۔عرفان احمدکی زیرتبصرہ کتاب اسی موضوع کے ایک اہم پہلو پر لکھی گئی ہے۔ اسلام پسندی کے نظریے کی بانی سمجھی جانے والی جماعت اسلامی ،ہندکے حوالے سے وہ اس نکتے سے بحث کرتی ہے کہ ہندوستان میں جمہوری عمل کے ساتھ اس کے تعلق اور کش مکش کی کیا شکل و نوعیت رہی ہے اور اس کے کیا اثرات اس کے فکری منہج اورعملی طریقہ کار پر مرتب ہوئے ہیں!
کئی سال کے مسلسل مطالعے اور پرمشقت فیلڈ ورک پر مشتمل یہ کتاب کئی حیثیتوں سے انفرادیت رکھتی ہے۔ اس کے مندرجات نہایت چشم کشا ہیں۔ اس کتاب میں پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ اس بات کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عالم اسلام کی اس نوع کی دوسری جماعتوں سے قطع نظر،پچھلی نصف صدی سے زیادہ عرصے سے جماعت خود کوجمہوریانے کے عمل میں پوری طرح کوشاں رہی ہے۔مصنف کے مطابق ،جماعت کی بنیادی فکر میں تبدیلی کی شروعات ۱۹۶۰ سے ہوئی جب علما وعوام کی اکثریت کی طرف سے ،جس میں علماے دیوبند پیش پیش تھے ،پوری طرح جماعت کے اس نظریے کو مسترد کردئے جانے پر جماعت نے دو الیکشن کے مکمل بائکاٹ کے بعد تیسرے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ (ص:۲۱۸) یہ دل چسپ بات ہے کہ ۱۹۵۱۔۵۲ کے الیکشن میں امیر جماعت نے الیکشن میں مسلمانوں کے حصہ نہ لینے کے لیے باضابطہ مہم چلائی ۔لیکن ۱۹۸۰ میں خود اپنے ارکان کو اس کی اجازت دینی پڑی (ص:۱۹۷) جب کہ۲۰۰۲ کے الیکشن میں اس نے سیکولرپارٹی کی جیت کے لیے باضابطہ انتخابی مہم چلائی۔(ص:۲۲۰)
اس کے بعدنصف صدی کے عرصے میں حکومت الہیہ کو اپنا اولین ہدف قرار دینے والی اورسیکولر جمہوریت کو ’’طاغوت‘‘ اور’’ جاہلیت ‘‘اور’’خنزیر کی طرح حرام‘‘ تصور کرنے والی جماعت اسی سے اپنا رشتہ استوار کرتی رہی ہے۔ مولانا مودودی نے علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی سمیت تمام جمہوری عصری اداروں کو ’’قتل گاہ ‘‘ قرار دیا تھا لیکن اب انہی قتل گاہوں میں جماعت اسلامی زندگی کی تلاش میں ہے۔ مصنف نے کتاب کے ساتویں اور آخری باب (ص: ۱۸۸۔۲۱۶) میں جماعت کے اس قلب ماہیت کا مدلل ومفصل تجزیہ پیش کیا ہے۔یہ پوری ’داستان عبرت‘ دلچسپ اور قابل مطالعہ ہے۔جماعت کی سر پرستی میں چلنے والے علی گڑھ کے گرین اسکول کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس پر سرے سے کسی آئڈیالوجی کا کوئی اثر نہیں ہے ۔اس میں اور عام اسکولوں میں کوئی فرق نہیں۔طلبہ کے والدین کی اکثریت اسکول کے پس منظر سے واقف بھی نہیں اس کے کارکنان کو اس کا احساس بھی نہیں۔ افراد اور ادارے کی سطح پر جماعت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جماعت کا دعوا خواہ جو بھی ہو، لیکن جماعت کی خاموش ترجیح سیکولر جمہوریت سے ہی قربت تلاش کرنا رہی ہے۔ اپنی تحقیق اور تجزیے کی بنیاد پر مصنف ا س خیال کو غلط ٹھہراتے ہیں کہ جماعت کے اندر یہ تبدیلی محض ظاہری ہے۔ ان کی نظر میں اس تبدیلی کا تعلق جماعت کے اندرون سے ہے ۔خود اس کے فکری ڈھانچے میں گہرائی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ (ص:۲)
کتاب کا چوتھا ،پانچواں اور چھٹاباب جماعت اسلامی کی فکر کی بنیاد پر قائم ہونے والی دو طلبہ تنظیموں:سیمی (SIMI) اور ایس آئی او ((SIO کے تقابلی مطالعے پر کے مختلف اہم پہلووں پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے مصنف نے علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی ،اعظم گڑھ میں جماعت کی طرف سے قائم مدرسے جامعۃ الفلاح میں فیلڈ ورک کے طور پر کافی وقت گزارا اور دونوں تنظیموں سے منسلک طلبہ کی تنظیمی و اجتماعی سرگرمیوں کوقریب سے دیکھنے ،پڑھنے کی کوشش کی ۔دونوں جگہوں پروہاں کے طلبہ اور کارکنان واساتذہ سے پیہم ملاقاتیں کرکے دونوں گروپ کے طلبہ وکارکنان کی ذہن کی ساخت اور اس کے تشکیلی عوامل کو سمجھنے کی جد وجہد کی تاکہ ایک ہی پس منظر رکھنے والے دونوں طلبہ گروپوں کے بالترتیب اعتدال پسندی اور ریڈیکلزم کے رویے کے بنیادی اسباب کا اندازہ کیا جاسکے۔مصنف کی نظر میں سیمی کی انتہاپسندانہ ذہنی تشکیل میں بنیادی طور پر ہندوتو طاقتوں کے اسی اور نوے کی دہائیوں کے عروج نے اہم رول نبھایا ہے ۔خاص طور بابری مسجد کے انہدام اور اس کے ما بعد ملک گیر فسادات نے سیمی کو ہندوستان جیسے ملک میں بھی جہاد کا راستہ اختیار کرنے پرمائل کیا۔ قابل غور ہیکہ مصنف کے مطابق ،۱۹۹۱ سے قبل سیمی کے اندر جہاد کا رجحان نہیں پایا جاتا تھا۔ ان کا مطالعہ جن نتائج پر مشتمل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ا ن کی نظر میں سیمی کا ظاہرہ (phenomenon) ہندوستان کے سیکولر جمہوری نظام کی ناکامی کی پیداوار ہے۔سیمی کے جماعت کی سر پرستی سے محرومی اسی کے ساتھ اس سے متعلق طلبہ کے سماجی پس منظر کو بھی کافی دخل رہا ہے ۔سیمی کے کارکنان شہری علاقوں اورخوش حال خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد اور سرپرستوں کی تعلیم مدارس کے ساتھ عصری درس گاہوں میں بھی ہوئی ہے۔وغیرہ۔ایس آئی او کی صورت حال بہت حد تک اس کے برعکس ہے۔جس کی قابل ذکر تفصیلات مصنف نے پیش کی ہیں۔
یہ مطالعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے اور مصنف کا اپنا نقطہ نظریہی ہے کہ اسلام پسندی کا نظریہ کوئی جامد اور بے لچک نظریہ نہیں ہے۔بلکہ وہ بہت سے دوسرے نظریات کی طرح ایک متحرک نظریہ ہے۔ جس میں زمانی و مکانی احوال وواقعات کے نتیجے میں ہمیشہ تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے۔ہم اسے اس پورے مطالعے کا حاصل کہ سکتے ہیں۔اسلام پسندی سے متعلق خاص طورپر مغرب کے سیاسی وفکری حلقوں میں اس وقت جونظریات پائے جاتے ہیں،یہ نظریہ بہت حدتک ان سے مختلف اور حوصلہ افزا ہے۔اس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حالیہ عرصے میں مختلف ملکوں کی اسلامی تحریکات کے اندر جو انتہا پسندانہ رجحانات سامنے آرہے ہیں وہ عبوری ہیں مستقل نہیں ہیں۔مشرق وسطی میں ان رجحانات کی پرورش میں وہاں کے غیر جمہوری سیاسی ماحول کا بنیادی دخل رہا ہے جس کی بقا انہی عالمی طاقتوں کی رہین منت ہے جوان تحریکات سے سب سے زیادہ خائف ہیں۔یہ پیراڈاکس ،فکر کا اہم مقام ہے۔
اسلامی اور سیاسی حلقوں کے لیے یہ مطالعہ ایک اہم بنیاد فراہم کرتا ہے کہ وہ ان کمزوریوں اورکا جائزہ لے سکیں جو بعض مسلم گروپوں میں انتہا پسندی کے فروغ کا سبب بنی ہیں یا بن رہی ہیں۔خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ عرفان احمد نے نہایت مدلل طور پر اس بات کوثابت کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ بعض مسلم حلقوں میں ریڈیکل رجحانات کی پیدائش اور افزائش کا تعلق مذہبی نظریات سے نہیں ،جیساکہ ہن ٹنگٹن اور برنارڈ لیوس جیسے لوگ کہتے رہے ہیں ،بلکہ اس کا تعلق سماجی حالات سے ہے۔مذہبی نصوص کی تشریح و تطبیق افراد او ر جماعتوں کی خود اپنی تاثر پذیر ذہنیت کا مر ہون منت ہوتی ہے۔یہ بشریاتی مطالعہ انتہا پسندی کی جڑوں کی تلاش و دریافت کے لیے کیے گئے حالیہ مطالعات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ہندوستان کے تعلق سے اپنی نوعیت کا یہ پہلا مطالعہ ہے۔جواس موضوع پرکا م کرنے والوں کے لیے ایک مضبوط زمین فراہم کرتا ہے۔امید ہے کہ اس کتاب سے سوچنے والوں کو نئی جہت ملے گی اور بہت سی ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہوسکے گاجواب تک مسلم اور غیر مسلم فکری و سیاسی حلقوں میں پائی جاتی رہی ہیں۔
ڈاکٹرعرفان احمد ہندوستان کے صوبہ بہار سے تعلق رکھنے والے نوجوان وذہین قلم کار ہیں۔طالب علمی کے زمانے سے مختلف اہم موضوعات پر لکھتے رہے ہیں۔ دہلی جواہرلال نہرو یونی ورسٹی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ اس وقت وہ آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔
(تبصرہ نگار: محمد وارث مظہری)
مولانا محمد اعظمؒ کا انتقال
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
مرکزی جمعیۃ اہل حدیث کے ناظم تعلیمات مولانا محمد اعظمؒ کی اچانک وفات پر بے حد صدمہ ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے شہر کے بزرگ علماء کرام میں سے تھے اور دینی تحریکات میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔ معتدل اور متوازن مزاج کے بزرگ تھے اور انھیں شہر کے تمام مکاتب فکر میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میرا ان سے کم وبیش ربع صدی تک دینی تحریکات کے حوالے سے تعلق رہا۔ جب بھی انھیں کسی اجتماعی مسئلے کی طرف توجہ کی دعوت دی گئی، انھوں نے بھرپور توجہ سے نوازا، حوصلہ افزائی کی اور تعاون فرمایا۔ وہ بھی ہر اہم موقع پر یاد کرتے تھے اور ہماری حاضری اور شرکت پر خوش ہوتے تھے۔ ضلعی امن کمیٹی میں ان کے ساتھ رفاقت رہی۔ حق کے اظہار کے ساتھ ساتھ متنازعہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ الجھانے کا ذوق رکھتے تھے اور اس سلسلے میں مکمل تعاون کرتے تھے۔
بیسیوں پبلک اجتماعات میں ان کے ہمراہ شرکت کا موقع ملا۔ شعلہ نوا خطیب تھے اور ان کی گفتگو، جوش وجذبہ کے ساتھ دلائل سے مزین ہوتی تھی۔ ابھی چند روز قبل ۲۶؍ فروری کو ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ڈویژنل سیرت کانفرنس میں ہم اکٹھے شریک ہوئے اور کافی دیر ہم ایک ساتھ بیٹھے رہے۔ اہل حدیث علماء کرام میں حضرت مولانا حکیم عبد الرحمن آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد دینی تحریکات کے بارے میں ہم زیادہ تر انھی سے رجوع کرتے تھے اور انھوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔
میں ذاتی طو رپر ان کی وفات پر ایک بزرگ دوست اور گرم جوش ساتھی کی جدائی کا غم محسوس کرتا ہوں اور دعاگو ہوں کہ اللہ رب العزت انھیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں اور پس ماندگان، متوسلین، تلامذہ اور احباب کو صبر وحوصلہ کے ساتھ ان کی حسنات کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین
السی: قیمت میں کہتر، فائدہ میں بدرجہا بہتر
حکیم محمد عمران مغل
جو خاندان ابھی تک تہذیب مشرق سے وابستہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی خطرناک امراض سے بچایا ہوا ہے۔ مثلاً تھکاوٹ، شوگر، امراض دل وگردہ، بلڈ پریشر، جسمانی دردیں وغیرہ۔ آج ریڈی میڈ ادویہ کا چلن ہے۔ گھر میں کوئی بزرگ اپنی زندگی کا کوئی قیمتی عمل بتاتا ہے تو تہذیب مغرب کے دل دادہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔
تہذیب مغرب نے ہمیں چاروں شانے چت گرا دیا ہے۔ ایک بیماری جاتی ہے، دوسری آتی ہے۔ بہت سے حضرات نے بتایا کہ فلاں ہم نے کیا نہیں، ہم سے بہ جبر کرایا گیا ہے، مگر اب پچھتا رہے ہیں۔ ان کے ازالے کے لیے بتائیں۔ میں نے ان کی خدمت کے لیے کافی تشخیص اور تحقیق اور مطالعہ کے بعد ایک نسخہ ترتیب دیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ موجودہ طرز بود وباش اور خور ونوش کو ترک کر دیں۔ ان شاء اللہ دور جدید کے تمام امراض سے بچ جائیں گے۔ یہ دوا یعنی السی پانچ ہزار قبل مسیح سے مستعمل ہے۔ السی کو باریک کر کے سفوف بنا لیں، لیکن ایک ہفتہ سے زیادہ نہ رکھیں۔ اس سے غذا جزو بدن بنتی ہے۔ بعض امراض کے جراثیم اور اندرونی رسولیوں کو ختم کرتا ہے۔ سورج کی روشنی برداشت نہ ہونا، موٹاپا، زائد چربی، انتڑیوں کے اورام، پھوڑے پھنسی، ٹھیک نہ ہونے والی کھانسی، حیض کے نظام کی تمام خرابیاں، ان سب امراض میں اس کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ چھاتی کا سرطان، تین ماہ میں ختم۔ اعلیٰ پروٹین اور مچھلی کا بدل اور مانع سرطان ہے۔ تقریباً دو چھوٹے چمچ کھانے کے بعد روزانہ کھائیں۔ شوگر میں خاصی کمی ہوگی۔ اس سے بلغمی امراض کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر پرہیز شرط اول ہے۔ اس کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے، مگر تیل سے کھانا نہ پکائیں۔ اس کا تیل بچوں کے لیے ٹانک ہے۔ بچوں کو اس کے پانچ قطرے پلاتے ہیں۔ آلو، گوبھی، دال ماش، چاول، پراٹھا، موجودہ دور کے تمام مشروبات سے قطعی پرہیز کریں۔ بہت سے خطرناک امراض سے بچ جائیں گے۔
مئی ۲۰۱۱ء
دین کے مختلف شعبوں میں تقسیم کار کی اہمیت
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
تبلیغی جماعت ہمارے اس دور میں دین کی دعوت، عام مسلمان کو دین کی طرف واپس لانے اور اصلاح وارشاد کی تجدیدی تحریک ہے جس کا آغاز شیخ الہند حضرت مولانا محمودحسن دیوبندی کے ماےۂ ناز شاگرد حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے ہاتھوں ہوا اور یہ ان کے خلوص وللہیت کا ثمرہ ہے کہ کم وبیش دنیا کا کوئی حصہ بھی دعوت وتبلیغ کی اس مبارک جدوجہد کی تگ وتاز سے خالی نہیں ہے۔ اس جدوجہد کا بنیادی ہدف عام مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑنا اور عمومی سطح پر دینی ماحول کو زندہ کرنا ہے جس کے اثرات وثمرات دن بدن پھیلتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔
حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی گزشتہ صدی کی ان تجدیدی شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے دین کے مختلف شعبوں کو اپنی جدوجہد کا میدان بنایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وعنایات سے اپنی پرخلوص محنت کے ساتھ پورے ماحول کو بدل دیا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مجلس میں تبلیغی جماعت کی خصوصیات وامتیازات پر گفتگو ہورہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میرے نزدیک حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام کو ایک شعبے میں محصور رکھا اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں سے تعرض نہیں کیا۔ گزشتہ دوصدیوں میں بہت سے مفکرین سامنے آئے اور کسی نہ کسی کام کی دعوت کو لے کر اٹھے۔ اگر وہ اسی کام کی دعوت اور اس کے فروغ تک خودکو محدود رکھتے تو شاید انہیں مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر انہوں نے بیک وقت داعی، متکلم، مناظر اور مفتی بننا بھی ضروری سمجھا جس سے ان کا کام نہ صرف خلفشار کا شکار ہوا، بلکہ وہ خود بھی متنازع حیثیت اختیار کرتے چلے گئے، لیکن یہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کی بصیرت وفراست تھی کہ انہوں نے دعوت وتبلیغ اور اصلاح وارشاد کے اس کام کو چھ نکات میں سمویا اور اپنی جدوجہد کو اسی دائرے میں محدود کردیا، جبکہ عقائد کی تعبیرات اور احکام ومسائل کے بارے میں وہ یہی کہتے رہے کہ ’’محلے کے مولوی صاحب سے دریافت کریں‘‘۔ میری طالب علمانہ رائے میں یہ بہت بڑی حکمت کی بات تھی۔
دین کے کاموں کی، مختلف شعبوں میں تقسیم فطری ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے چلی آرہی ہے۔ حدیث کی روایت کا اہتمام کرنے والے صحابہ کرام اپنا الگ امتیاز رکھتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر وتاویل میں امتیازی شخصیات الگ نظر آتی ہیں، فقہ واستنباط کا ذوق رکھنے والی شخصیات دوسروں سے ممتاز دکھائی دیتی ہیں، کچھ صحابہ کرام فتنوں سے آگاہی اور ان کی نشان دہی کے میدان میں جداگانہ ذوق کے حامل رہے ہیں، بعض ممتاز صحابہ کرام کا قرآن کریم کے حفظ وقرأت میں الگ سے نام لیا جاتا ہے، جرنیل صحابہ کرام کا امتیاز بھی موجود ہے اور سیاست وانتظام میں معروف صحابہ کرام کو بھی الگ سے گنا جاسکتا ہے، البتہ اس دور میں یہ بات نمایاں تھی کہ کسی شعبہ میں دین کے کام نے ’’حزبیت‘‘ کا رنگ اختیار نہیں کیا تھا اور اپنے اپنے شعبہ میں کام کرتے ہوئے دوسرے شعبوں میں تعاون واشتراک کا بھرپور جذبہ ہر سطح پر کارفرما تھا اور اس لیے یہ تقسیم کار اپنے فطری دائرہ میں محدود تھا اور اس کے ثمرات سے امت نے بڑے عرصہ تک استفادہ کیا۔
بعض دوستوں کو یہ اعتراض ہے کہ دین کے فلاں فلاں کام تبلیغی جماعت والے نہیں کرتے اور انہوں نے دین کو ایک محدود دائرے میں بند کردیا ہے۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت نے دین کو محدود نہیں کیا، بلکہ اپنی جدوجہد کے دائرے کو محدود کیا ہے جو تقسیم کار کے فطری اصول کے مطابق ہے اور حکمت ودانش کا تقاضا ہے۔ تبلیغی جماعت والے بنیادی طور پر دوتین کام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک عام مسلمان کو جس کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گھیرگھار کے مسجد کے ماحول میں لے آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس شخص کا مولوی صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اسے بہلاپھسلاکر مولوی صاحب کے پیچھے نماز میں کھڑا کردیتے ہیں اور تیسرا یہ کہ چند روز کے لیے اسے اپنے ساتھ چلاکر دین کی بنیادی باتیں، جن میں عقائد، احکام اور اخلاقیات شامل ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تینوں کام وہ کررہے ہیں اور جس عمومی سطح پر وہ کام کرتے ہیں، کوئی اورادارہ نہیں کررہا۔ ہمارے پاس مساجد ومدارس میں جو لوگ چل کر آتے ہیں، ہماری محنت انہی تک محدود رہتی ہے، مگر تبلیغی جماعت والے چل کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں دین کے ماحول میں آنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ مسجد ومدرسہ کی آبادی بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اگر ان دوستوں کے کام کو اسی سطح پر محدود رکھتے ہوئے اس سے اگلا کام خود کریں کہ ان کے بھرتی کیے ہوئے لوگوں کی دین کے دیگر شعبوں میں تعلیم وتربیت کا اہتمام کریں اور یہ طے کرلیں کہ بھرتی کا کام ان کا ہے اور اس سے اگلا کام ہمارا ہے تو میرے خیال میں کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی، مگر بدقسمتی سے ہماری اس طرف اجتماعی طور پر توجہ نہیں ہے جس سے دھیرے دھیرے ’’حزبیت‘‘ کا ماحول پیدا ہورہا ہے۔
دین کے مختلف شعبوں میں ہونے والا کام جب تک حزبیت (جماعتی گروہ بندی)سے بچتے ہوئے باہمی تعاون واشتراک کے ماحول میں ہوتا رہے گا، اس کے ثمرات ونتائج مثبت رہیں گے، لیکن جب اس میں تقسیم کار کی بجائے حزبیت کا رجحان غالب ہوگا تو وہ شکایات ضرور پیدا ہوں گی جن کا مختلف حلقوں کی طرف سے اظہار شروع ہوگیا ہے، اس لیے کہ حزبیت کا خاصہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ: ’’کل حزب بما لدیہم فرحون‘‘۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گروہ ’’حزب‘‘ بن جائے گا تو صرف اپنا کام ہی اسے اچھا لگے گا اور دوسرے کسی گروہ کے کام کو اچھا کہنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی الجھن یہی ہے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کی جانے والی محنت تقسیم کار کی بجائے حزبیت کا رنگ اختیار کرتی جارہی ہے اور یہ صرف تبلیغی جماعت کے حوالے سے نہیں، بلکہ دوسرے بہت سے دینی شعبوں میں کام کرنے والے گروہوں کے جذباتی کارکنوں کی نفسیات بھی یہی ہے کہ انہیں صرف اپنا کام اچھا لگتا ہے، وہ اسی کام کے تقاضوں کو دین کے مجموعی ماحول کا تقاضا قرار دینے لگتے ہیں اور دوسرے کسی شعبے کے دینی کام کی اگر وہ نفی نہ بھی کریں تو اس کا تذکرہ ایسے انداز میں کریں گے، جیسے اس کام کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔
تبلیغی جماعت کے کام میں ایک اور بات بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ جہاں علمائے کرام اس کام میں شریک ہیں اور ان کی راہ نمائی میں کام ہورہا ہے، وہاں کی صورت حال اور ہے اور جہاں علمائے کرام اس کام سے الگ تھلگ ہیں، وہاں کی صورت حال اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے علمائے کرام اس کام کے لیے وقف ہوجائیں اور اپنے اصل کام کو حرج میں ڈال دیں، بلکہ تعلیم وتدریس اور امامت وخطابت کا حرج کرکے کسی بھی دوسرے دینی کام کے ساتھ خود کو مختص کرلینا ویسے بھی دین کے مفاد کے خلاف بات ہوگی۔ دین کے کسی شعبے میں اس شعبہ کے دوستوں سے تعاون کرنے کا مطلب اپنے دینی کام کو کمزور کرنا نہیں، بلکہ باہمی تعاون کی ایسی فضا پید اکرنا ہے جس سے دونوں ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنیں، اس لیے میری علمائے کرام سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ اپنے کام کو پوری طرح سرانجام دیتے ہوئے اس میں کوئی کمزوری لائے بغیر تبلیغی جماعت کے ساتھ اس درجہ کا تعلق ضرور قائم رکھیں کہ وقتاً فوقتاً اس میں تھوڑا بہت وقت لگاتے رہیں تاکہ باہمی ربط وتعلق موجود رہے اور ہم سب ایک دوسرے کو کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہوئے باہمی خوبیوں سے استفادہ کر سکیں۔ خود میرا معمول سالہاسال سے یہ ہے کہ سال میں ایک سہ روزہ پابندی کے ساتھ تبلیغی جماعت میں ان کے نظم کے مطابق لگاتا ہوں جو عام طورپر عیدالاضحی کی تعطیلات میں ہوتا ہے اور یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تبلیغی جماعت کا علمائے کرام کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی نیت کے علاوہ خود بھی اس ماحول سے بحمداﷲ استفادہ کرتا ہوں اور دینی فوائد محسوس کرتا ہوں۔
والدگرامی حضرت مولانا محمد سرفرازخان صفدر کا ذوق ومعمول بھی یہی تھا کہ وہ تبلیغی جماعت کے کام کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اسے بنیادی طور پر دین کا کام سمجھتے ہوئے سراہتے بھی تھے، البتہ کچھ تحفظات بھی رکھتے تھے جن کا اظہار انہوں نے کبھی عمومی ماحول میں نہیں کیا، بلکہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے ان تحفظات پر بوقت ضرورت بات کی اور اسے اسی سطح پر رکھا ہے۔ حضرت والدگرامی کے ساتھ میں بھی ایک خادم کے طور پر اکابر علمائے کرام کے اس وفد میں شریک تھا جس میں مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ ، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ، مولانا حسن جان شہید، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید، مولانا سعیداحمدجلال پوری شہید، مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید اور غالباً مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم بھی شامل تھے۔ ان بزرگوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر بھارت سے تشریف لانے والے سرکردہ تبلیغی بزرگوں سے ملاقات کرکے انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا اور ان بزرگوں نے ان تحفظات کو تسلیم کرتے ہوئے اصلاح احوال کی کوشش کا وعدہ کیا تھا۔ اس واقعہ کے تذکرہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طریق کار یہ تھا کہ کسی بھی دینی کام میں اگر کام کرنے والوں سے کچھ شکایات ہیں تو انہیں شکایات کے درجہ میں ہی رکھا جائے۔ ہمارے اکابر کی احتیاط کا اس سے اندازہ کرلیا جائے کہ اپنی گفتگو میں انہوں نے پاکستان کے تبلیغی بزرگوں کو بھی شامل نہیں کیا تھا کہ بات محدود سے محدود رہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود تبلیغی جماعت کا کام دین کا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے اور دین کی دعوت وتبلیغ کے ساتھ عام مسلمان کی اصلاح وارشاد کا کام ہے جس کے ساتھ تعاون دین کے تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔
فکری و سیاسی اختلافات میں الزام تراشی کا رویہ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حامد میر صاحب اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی یادداشتوں کا سہارا لے کر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے درویش صفت بزرگ پر ایک سیاسی تحریک میں غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ ساز باز کا الزام عائد کر دیں گے۔
حامد میر صاحب سینئر صحافی اور کالم نگار ہیں، مطالعہ وتحقیق اور تجزیہ کی دنیا کے آدمی ہیں، البتہ مطالعہ وتحقیق کو کسی بھی موقع پر اپنے ڈھب پر ڈھال لینے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہیں، اسی لیے جب وہ کوئی بات خود سے کہنا چاہتے ہیں تو انھیں کوئی نہ کوئی حوالہ مل جاتا ہے اور وہ یہ تحقیق کیے بغیر کہ یہ حوالہ سند کی دنیا میں کیا درجہ رکھتا ہے اور درایت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی بنیاد پر اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ انھوں نے بھٹو مرحوم کی پھانسی کے کیس کو ’’ری اوپن‘‘ کیے جانے کی درخواست پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ایک حالیہ کالم میں ۱۹۷۷ء کی تحریک مصطفی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ تحریک بھٹو مرحوم کے خلاف امریکہ کے کہنے پر چلائی گئی تھی اور اس میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ او رمولانا عبید اللہ انورؒ کے ساتھ لاہور کے برطانوی قونصل جنرل کا مسلسل رابطہ تھا۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون سی تحریک کس کے کہنے پر چلائی گئی تھی، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور جنوبی ایشیا کی کوئی سیاسی تحریک بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ وہ فلاں قوت کے اشارے پر چلائی گئی تھی، حتیٰ کہ تحریک پاکستان کے بارے میں خان عبد الولی خان مرحوم اور لاہور ہائی کورٹ کے ایڈووکیٹ جناب محمد نورالحق قریشی کے پیش کردہ بھاری بھرکم حوالہ جات پر اعتماد کیا جائے او رحامد میر صاحب کے طرز استدلال کو اختیار کیا جائے تو اس کے پیچھے بھی امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی مقاصد اور ایجنڈے کی جھلک صاف نظر آنے لگتی ہے۔
یہ بات ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ بن گئی ہے کہ ہم اپنے سوا کسی اور کو کوئی سیاسی موقف طے کرنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے، اس کی دیانت پر اعتماد کرنے کی بجائے اس کے ڈانڈے کسی نہ کسی دشمن کے ساتھ ملا دینے میں نفسیاتی تسکین محسوس کرتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک سیمینار میں ملک کے ایک معروف دانش ور نے بعض معاشی مسائل کے حوالے سے چند معروف علما کے موقف پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ انھوں نے فلاں قوت سے پیسے لے کر یہ موقف اختیار کیا ہے۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنے خطاب میں گزارش کی کہ جب ہمارے ملک کی اعلیٰ سطح پر پائی جانے والی دانش کا یہ حال ہے کہ بعض حضرات خود سے اختلاف رکھنے والوں کو کسی دوسرے کا ایجنٹ بتائے بغیر اپنا موقف پیش کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو ایک غریب اور عام شخص کا کیا حال ہوگا؟ ہم میں یہ حوصلہ اور اخلاقی جرات ہی نہیں رہی کہ ہم کسی دوسرے کے موقف اور رائے کو اس کا حق سمجھتے ہوئے اس کی دیانت پر اعتماد کریں اور یہ کہہ کر اس سے اختلاف کریں کہ اس نے اپنی صواب دید اور دیانت کے مطابق جو موقف خلوص کے ساتھ اختیار کیا ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے اور اس پر کوئی الزام عائد کیے بغیر ہم دلیل کے ساتھ اس اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں۔
اہل علم کے ہاں راوی اور روایت کا درجہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی روایت کے قبول یا عدم قبول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ حامد میر صاحب نے اس واقعہ میں جن صاحب کو بطور راوی پیش کیا ہے، ان کا اخلاقی حدود اربعہ کیا ہے؟ مگر میں حضرت مولانا عبید اللہ انورؒ کو جانتا ہوں اور اتنا قریب سے جانتا ہوں کہ شاید ہی ان کا کوئی اور رفیق کار اس درجے میں اس بات کا دعویٰ کر سکے۔ وہ اس مزاج کے بزرگ ہی نہیں تھے۔ یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کہ مولانا عبید اللہ انور کے ساتھ کسی سفارت کار کے مسلسل رابطے تھے، اس لیے کہ وہ تو گوشہ نشین اور خلوت پسند قسم کے بزرگ تھے۔ بالخصوص ایوبی آمریت کے خلاف لاہور میں ایک احتجاجی جلوس کی قیادت کے دوران پولیس کے لاٹھی چارج سے ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہونے کے بعد سے وہ معذور بھی ہو گئے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت اپنے گھر کے بالا خانے میں گزرتا تھا ہاں وہ مطالعہ اور ذکر الٰہی میں شب وروز مصروف رہتے تھے۔ ہم چند لوگ جو ان کے قریب ترین ساتھی شمار ہوتے تھے، کسی اشد ضرورت کے بغیر انھیں ملاقات اور تشریف آوری کی زحمت نہیں دیا کرتے تھے اور وہ کئی کئی دن اپنے خاص مریدوں اور ساتھیوں کو بھی میسر نہیں آتے تھے۔ ان کے گھر کے زیر سایہ مدرسہ قاسم العلوم میں جمعیۃ علماء اسلام کے اہم اجلاس ہوتے تھے اور ہمیں ان سے دریافت کرنا پڑتا تھا کہ وہ اجلاس میں شریک ہونے کی پوزیشن میں ہیںیا نہیں؟ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایک غیر ملکی سفارت کار کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور سیاسی تحریک کو مخصوص رخ پر چلانے کے لیے کوئی متحرک کردار ادا کر رہے تھے، لطیفہ اور ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟
حامد میر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ’’سیاسی چاند ماری‘‘ کا شوق ضرور پورا کریں کہ آج کل سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ کالم نویسوں کے پاس بھی اس کے سوا کوئی مشغلہ باقی نہیں رہا، لیکن کم از کم ایسے بزرگوں کو تو معاف کر دیا کریں کہ جن کی شرافت، دیانت اور ثقاہت کے سہارے ہمارے معاشرے میں ان مقدس الفاظ کا کچھ نہ کچھ بھرم قائم ہے۔ کیا وہ اس رہے سہے بھرم کو بھی ختم کر دینے کی خواہش رکھتے ہیں؟
دعوت الی اللہ کا فریضہ اور ہمارے دینی ادارے (۱)
مولانا محمد عیسٰی منصوری
دعوت
اسلام کی روح اورطاقت: حضرات انبیا کا بنیادی اور اصل کام دعوت الی اللہ یعنی انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا۔ وہ انسانوں کو اللہ کا تعارف کرواتے، اللہ کی عظمت وبڑائی دلوں میں اتارتے، ان میں آخرت کی فکر پیدا کر کے ان کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف موڑتے اور انہیں اللہ کے لیے مرنا اور جینا سکھاکراللہ والا بنادیتے۔ نبیوں کا طریقہ براہ راست انسانوں تک پہنچ کر انہیں ایمان واسلام پہنچاناتھا۔ انبیاء علیہم السلام دین کے دوسرے کام تعلیم وتعلم، تزکیۂ نفس، ذکروتلاوت، صدقہ وخیرات، دعوت کے ضمن میں اور تابع کرکے انجام دیتے تھے۔ ان کی پوری زندگی اور زندگی کے ہر دن اور ہرلمحے کا بنیادی کا م دعوت ہی تھا۔ خاتم النبیین اور آپ کے صحابہؓ کازندگی بھریہی اصل مشغلہ تھا، البتہ کبھی کبھی دعوت کی راہ کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے قتال کی بھی نوبت آجاتی تھی۔ دعوت کی بدولت ہجرت کے بعد دس سال میں روزانہ ۲۷۴ میل کے حساب سے اسلام پھیلتا گیا۔ آپ ؐکی وفات تک کم وبیش دس لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کے زیرنگیں آگیاتھا۔ آپ کے بعد چالیس سال کی مختصر سی مدت میں تقریباً ۶۵ لاکھ مربع میل علاقہ پر اسلام کی عمل داری قائم ہوگئی، یعنی اس دور کے تین معلوم براعظموں (ایشیا، افریقہ اوریورپ کے بڑے حصہ) پر جسے آج مسلم ورلڈ یا عالم اسلام کہاجاتاہے۔ یہ درحقیقت پیغمبراسلامؐ اور آپ ؐکے صحابہ کرامؓکی دعوت کا پھل ہے۔ بعدکے ادوار میں مسلمان تدریجاً دعوت سے دور ہوتے گئے، اگرچہ بعد کے ادوار میں بھی کسی نہ کسی درجہ میں اسلام کی اشاعت ہوتی رہی اور اس اشاعت اسلام میں دیگر عوامل نے بھی تھوڑا بہت کردار ادا کیا، لیکن دعوت اور غیردعوت کے ادوار میں اشاعت اسلام میں نمایاں فرق یہ رہا کہ جن خطوں اور علاقوں میں دعوت کے ذریعہ اسلام پہنچا، وہ آج تک ایمان پر قائم اور پوری طرح محفوظ ہیں اور جن خطوں میں عسکری فتوحات یا دیگر عوامل سے اسلام پھیلا، عسکری قوت کے کمزور پڑنے کے ساتھ وہاں دوبارہ کفرکی عمل داری قائم ہوگئی۔
دین کے اجتہادی شعبے اصل (دعوت)کے ساتھ ہی پورا فائدہ دیں گے :بعدکے ادوار میں دعوت کے بجائے دین کے دیگر اجتہادی شعبوں کی طرف توجہ مرکوز ہوجانے کی وجہ سے ایک طرف نئے نئے خطوں اور علاقوں میں اسلام کی اشاعت کی رفتار سست وکمزور ہوتی گئی، دوسری طرف خود مسلمانوں میں ایمانی وعملی ضعف وکمزوری درآئی جس کی وجہ سے طرح طرح کے اعتقادی وفکری فتنوں وگمراہیوں نے جنم لیا حتیٰ کہ آج یہ حالت ہوگئی کہ اگر مسلمان کہلانے والوں کو قرآن وسنت کی کسوٹی پر پرکھاجائے تو انہیں مسلمان کہنا مشکل ہوگا۔ دین کے دیگر شعبے جب تک اصل کام (دعوت) کے ضمن میں چلتے رہے، ان میں ترقیات، فوائد اور خیروبرکت رہی اور جب اصل (دعوت)کی جگہ دین کی اجتہادی شکلوں، تعلیم وتعلم، درس وتدریس، تصوف وتزکیہ، تذکیر وتبلیغ نے لے لی یعنی دعوت کے بجائے اجتہادی شعبے ہی رہ گئے تو ان میں رسمیت آکر طرح طرح کی خرابیاں پیداہونے لگیں، کیونکہ صرف دعوت ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعہ داعی کا ربط وتعلق ایک طرف براہ راست اللہ سے اور درسری طرف لوگوں سے استوار رہتاہے۔ جب تک یہ تعلق قائم رہے، کفر اور باطل طاقتیں اپنی سازشوں اور کوششوں میں کامیاب نہیں ہوپاتیں۔ حضرت امام مالک ؒ کا قول مشہور ہے کہ اولین دور یعنی دور نبوت میں امت کی صلاح وفلاح، ترقی وکامیابی جس طریقہ پر ہوئی، آخری دور میں بھی اور (درمیان میں بھی) اسی راہ (دعوت) سے ہوگی۔
حق وباطل کی جنگ میں سنت الٰہی
حق وباطل کی جنگ میں یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی ہے کہ باطل کو مادّی وسائل واسباب نہایت فراوانی سے دیے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کوجو اسباب اور سازوسامان عطا کیا جاتا ہے، وہ ہے’’دعوت اور دعا‘‘ یعنی دن کو، جان کھپاکر لوگوں کو اللہ کی بات پہنچانا اور رات کو اللہ کے سامنے آہ وزاری اور دعا میں مشغول رہنا۔ دعوت کی بدولت داعی کے ساتھ اللہ کی خاص نصرت وطاقت شامل حال ہوجاتی ہے، ایسی طاقت جس کا مقابلہ کوئی دنیوی طاقت نہیں کر سکتی۔ گویا دعوت کا عمل دنیا میں بھی غلبہ وکامرانی کی شاہ کلید اور گہری حکمت ہے۔ داعی کسی قوم وملک کو دعوت دے کر گویا اسے اس سے بے انتہا بڑی قوت وطاقت سے بھڑا یعنی ٹکرا دیتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر وہ قوم وملک یامطیع (مسلمان) ہو جاتا ہے یا خداکا غیبی نظام اس کے خلاف پڑ کر اسے تباہ کردیتاہے، چنانچہ دور نبوت میں بھی یہی ہوا۔ اُس وقت دنیا پر عملاً دو سپر پاورز کی عمل داری قائم تھی۔ ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر۔ اگر صحابہ کرامؓ ان دونوں سُپر پاورز کے مقا بلے کا مادّی سازوسامان، اسلحہ واسباب اکٹھا کرتے تو شاید صدیوں تک ان کے مقابلے کے اسباب ووسائل جمع نہ کر پاتے۔ صحابہ کرامؓ نے کامیابی کی مختصر راہ اختیار فرمائی، یعنی ان کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ انکار کرنے پر اللہ کی غیبی طاقت ونظام ان کے خلاف ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گنتی کے چند سالوں میں صدیوں سے جمی جمائی دونوں عظیم سلطنتیں اس طرح مٹ گئیں جیسے نمک پانی میں تحلیل ہوکر ختم ہو جاتا ہے۔ آج ان دونوں سپرپاورز کی سرزمین ہی اصل دارالاسلام ہے۔
ملت اسلامیہ کے لیے واحد راہ عمل صرف دعوت ہے
غورکیاجائے تو آج کے دور میں بھی ملت اسلامیہ اور عالمی کفریہ طاقتوں کے مابین طاقت اسباب ،وسائل کاتقریباً وہی تناسب ہے جوآج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے تھا، بلکہ جدید سائنسی وٹکنالوجی ترقی نے اسلام اور کفر کے درمیان طاقت کے تناسب میں فرق کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اگر دور نبوت میں طاقت کا تناسب ایک اور دس کا تھا تو اب ایک اور ہزار کا ہو گیا ہے۔ مثلاً غزوۂ بدر میں صرف تعداد کا فرق تھا۔ ایک طرف تین سو تیرہ ہیں، دوسری طرف گیارہ سو، مگر دونوں کے پاس دستی ہتھیار تھے۔ اب جدید سائنس نے الیکٹرونک اسلحہ دے کر ایک فرد کو اس قابل بنادیاہے کہ وہ ایک بٹن دباکرپورے ملک کو تباہ کرسکتاہے،اس لیے اب ملت اسلامیہ کے لیے غلبہ وکامرانی حاصل کرنے کی صرف ایک ہی راہ باقی رہ گئی ہے جو دور نبوت میں تھی، یعنی دعوت الیٰ اللہ۔ اشاعت اسلام کی پوری تاریخ دعوت کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے گزشتہ چودہ سو سالہ دور میں مراکش سے انڈونیشیا تک جو کچھ حاصل کیا، وہ دعوت ہی کی بدولت حاصل کیا اور جو کھویا، دعوت میں کوتاہی سے کھویا۔ آج دنیا بھرمیں مسلمانوں کو جو سزامل رہی ہے، وہ درحقیقت دعوت چھوڑنے کی سزاہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کی امانت یعنی ایمان واسلام ان تک نہیں پہنچایا ،اس لیے ہم اللہ اور انسانیت دونوں کے مجرم بن گئے۔
ملت اسلامیہ کے تین دور
حضرت جی مولانا یوسفؒ نے ۱۹۶۳ء میں تقریباً تین گھنٹے دعوت کی تاریخ پر ایک تقریر فرمائی (جو بندہ نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر قلم بند کی تھی، جلدہی ان شاء اللہ شائع کرنے کا ارادہ ہے۔) اس میں حضرت ؒ نے ملت کے تین دور بتائے۔ پہلادور جس میں دعوت اصل اور محور کے درجہ میں تھی، علم وذکر ضمن میں تھے۔ اس دور میں کس طرح آناً فاناً دنیا میں اسلام پھیلا۔ پھر خلفائے راشدین کے بعد جو بر سر اقتدار طبقہ تھا، وہ دعوت چھوڑکر عیش وعشرت میں پڑگیا تو مخلصین نے علم کو اصل اور محور بنا کر سارے مجاہدے، مشقتیں اور تکالیف جو پہلے دور میں دعوت کی خاطر برداشت کیے جاتے تھے، دوسرے دور میں علم کی خاطر یعنی حدیث ،تفسیر، سیرت اور دیگر دینی علوم کے محفوظ کرنے کی خاطر اختیار کیے۔ اس دوسرے دور میں علم اصل اور محور تھا، دعوت وجہاد اور ذکر ضمن میں تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک سال میں چھ ماہ درس حدیث دیتے اور چھ ماہ جہاد کرتے تھے۔ ذکر بھی تھا، مگر اصل محور کے درجے میں بنیادی توجہ علم پر یعنی احادیث جمع کرنے، سیرت ومغازی وتفسیرکے محفوظ کرنے اورمسائل استنباط کرنے وغیرہ وغیرہ پر تھی۔ جب اہل علم میں بگاڑ آگیا، علماء بادشاہوں کے قرب اور دنیوی عہدوں ومناصب کے حصول اور مال اور متاعِ دنیا جمع کرنے میں لگ گئے تو مخلصین نے اللہ کے ذکر کے ذریعہ تزکیۂ قلوب، اخلاص اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کر دی۔ اس طرح تیسرا دور شروع ہو ا۔ اس تیسرے دور میں علم بھی تھا، دعوت بھی تھی ، مگر اصل اور محور کے درجہ میں ذکر تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آخری دور میں سات سو مبلغین دعوت کے لیے جنوبی ہند روانہ کیے، مگر اس تیسرے دور میں محور اور اصل کے درجے میں ذکر الٰہی تھا۔
پھر حضرت ؒ نے تفصیل سے ان تینوں ادوار کا فرق بیان فرمایا۔ مثلاً پہلے دور میں کفاراورخدا کے دشمنوں کو کثرت سے ہدایت مل رہی ہے، اسلام تیزی سے ملکوں اور قوموں میں داخل ہورہاہے، کٹڑ سے کٹڑ اسلام کے دشمن ایمان لارہے ہیں۔ دوسرے دور میں عباسی خلیفہ حضرت سفیان ثوریؒ کا معتقد ہے، ان کے خط کو احترام میں آنکھوں سے لگاتاہے، سرپر رکھتاہے، بوسہ دیتاہے، مگر ان کی لکھی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ حضرت ؒ نے فرمایا کہ قیامت تک امت پر ان تین ادوار میں سے کوئی نہ کوئی دور رہے گا۔ جب محور اور اصل دعوت ہوگی تو پہلے دور کی برکتیں فوائد وثمرات ملیں گے اور جب ذکر محور ہو گا تو تیسرے دور کے فوائد وبرکات حاصل ہوں گے۔ حضرت ؒ نے یہ مفصل تقریر خیر القرونِ قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کی تشریح وتفہیم کے ذیل میں فرمائی تھی۔
دعوت ہر مسلمان کا اصل کام اور فریضہ
اسلام ایک دعوتی دین ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: ’’کہہ دیجیے، یہ میراراستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتاہوں بصیرت کے ساتھ اور میرے متبعین کا بھی‘‘ (القرآن) پیغمبر اسلام نے اس امت کی تربیت دعوت ہی کے راستہ سے فرمائی۔ ہر شخص کلمہ پڑھتے ہی دعوت کے کام میں لگ جاتاتھا۔ حجۃ الوداع کے آخری پیغام میں آپؐ نے قیامت تک کے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب تم کو رہتی دنیا تک میرا پیغام انسانیت کے ہر ہر فرد تک پہنچاناہے۔ پوری انسانیت آپ کی امت قرار دی گئی، امت اجابت یا امت دعوت۔ جیسے باپ آخری وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت کر جائے کہ میری میراث دوسرے بیٹے تک بھی پہنچادینا، لیکن وہ بیٹا ساری وراثت اپنے ہی پاس رکھ لے، دوسرے بھائی تک نہ پہنچائے تو وہ باپ کا بھی مجرم ہوگا اور دوسرا بیٹا (غیر مسلم) بھی اس کا دشمن بنے گا۔ آج ساری دنیا کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ ہم نے ان کا حق مارا ہے، ان کا ورثہ (ایمان واسلام ان تک نہیں پہنچایا)۔ غرض ایک مسلمان کا اصل کا م اور زندگی کا مشن دعوت ہی ہے، اس کے بغیر نہ وہ کا مل مسلمان بن سکتاہے اور نہ دنیا میں اسلام فاتح وغالب رہ سکتاہے۔ رہا جہاد تو وہ نام ہے دین پھیلانے میں اپنی ساری قوت وتوانائی حتیٰ کہ جان تک قربان دینے کا۔ جہاد، دعوت ہی کاآخری مرحلہ ہے، یعنی جب طاقت وقوت سے دعوت کو روکا جائے تو طاقت ہی سے وہ رکاوٹ دور کردی جائے۔ موجودہ دور میں دشمنان اسلام بالخصوص مغرب کی صہیونی وصلیبی قوتوں نے ایک طر ف ابلاغ کے تما م وسائل پر جن کے ذریعے انسانوں کے دلوں تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، اور دوسری طرف اسلحہ وطاقت کے تما م وسائل پر مکمل قبضہ وکنٹرول کر کے جہاد کے خلاف شرانگیز پروپیگنڈا کر رکھا ہے اور مغرب سے مرعوب ومتأثر ہمارے بالائی طبقات، حکمراں، فوج اور جدید تعلیم یافتہ طبقے نے بھی لفظ جہاد کو طعنہ بلکہ گالی بنادیا ہے۔ یہ لوگ ہر جگہ جہاد سے برأت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ سارا قرآن جہاد کی اہمیت وفضیلت سے بھراپڑا ہے، لیکن اسلام کا مقصود قتال نہیں، دعوت ہے۔ قتال ناگزیر حالات میں مجبوراً سرجن کے آپریشن کی طرح آخری آپشن کے درجہ میں ہے۔
ایمان ونفاق کے درمیان فرق کرنے والی چیز دعوت و جہاد ہی ہے
ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایمان ونفاق کے درمیان امتیاز، دین پھیلانے کی جدوجہد (دعوت وجہاد) سے ہی قائم ہوتا ہے۔ دور نبوت کے منافقین نمازو روزہ، ذکر وتلاوت، صدقہ وخیرات سب کچھ کرتے تھے،امتیاز دعوت وجہاد کے موقع پر ہی ہوتا تھا۔ آخری غزوہ تبوک میں تیس ہزار صحابہ کرام شریک ہوئے، صرف تین نہ جاسکے۔ اس پر ان کے ساتھ توبہ قبول ہونے تک معاشرتی طور پر کا فروں اور منافقوں جیسا برتاؤ ہوا۔ اس سے پتہ چلتاہے کہ نبی آخرالزماںؐ کے امتی کے لیے دین پھیلانے کی جد وجہد یعنی دعوت کے بغیر صرف دین پر چلنا ہرگز کافی نہیں۔ بقول عصرحاضر کے ایک داعی کے آج دین پھیلانے کے لیے لوگوں میں مارے مارے پھرنا فضیلت اور ثواب کی چیز ہے۔ وہ وقت (ظہور مہدی) قریب ہے جب یہ دور نبوت کی طرح فرض وواجب ہوگا، دین کی خاطر نہ نکلنے والے کو منافق وکافر قرار دیا جا ئے گا۔ قرآن کاارشاد ہے: کامل مؤمنین صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پراور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، پھر ذراشک نہیں کیا، پھر اپنی جان ومال سے اللہ کی راہ میں کو شش وجہاد کیا۔ صرف یہی لو گ (ایمان کے دعوے)میں سچے ہیں۔‘‘ (سورۂ حجرات آیت ۱۵)
ہمارے تمام مصائب اور مشکلات کا اصل سبب
آج دنیا کے ہر ملک میں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں مثلاً تعلیم میں پچھڑجانا، اقتصادی پسماندگی، سیاسی بے حیثیتی، ہر طرح کی ناانصافی، ہولناک مظالم، نسل کشی (دیکھا جائے تو دنیا بھر کی دجالی طاقتوں نے ہر ملک میں اسپین کی تاریخ دہرانے کی تیاری کر لی ہے) ،یہ ہولناک حالات ومصائب اصل مرض نہیں، مرض کی علامت ہیں۔ ہمارا اصل مرض یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑلیا اور دین کو پھیلانا چھوڑدیا جس کی وجہ سے ہم انسانیت کے خیر خواہ بننے کے بجائے حریف بن گئے۔ آج ہم دنیا بھر میں اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، عراق وافغانستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر وفلپائن میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اور دنیا کے انسانوں کی نظر میں مظلوم ہیں اور دوسرے لوگ ظالم، لیکن کبھی کبھی میں سوچتاہوں کہ دنیا کے انسانوں تک ان کی امانت (ایمان واسلام) نہ پہنچانے کی وجہ سے اصل ظالم ہم ہی ہیں کہ ہم نے ان کا حق ماراہے، باپ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کی امانت اس کے دوسرے بیٹے تک نہیں پہنچائی۔ اللہ اور رسول ؐنے انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہمیں جو ذمہ داری وامانت سونپی تھی، ہم نے خیانت کی، ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ایمان واسلام وہ دولت ہے جس کے بغیر دنیا کا ہر فرد بشر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاکت میں پڑجائے گا۔ ہم انسانیت کے حق میں اتنے بے رحم وظالم ثابت ہوئے کہ ان بے چاروں کو دائمی ہلاکت وبربادی سے بچانے کی ذرافکر نہ کی، اپنی دنیا بنانے میں مگن رہے تو اللہ نے اس جرم کی پاداش میں انہی لوگوں کے ذریعہ ہماری دنیا کو جہنم بنادیا۔
دنیامیں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی؟ دنیامیں اسلام دینی اداروں سے نہیں، دعوت سے پھیلاہے، مثلاً بر صغیر کے مغربی حصہ (پاکستان) میں زیادہ تر اسلام کی اشاعت اس دور میں ہوئی جب مسلمانوں میں کسی حد تک دعوت کا جذبہ موجود تھا، یعنی محمد بن قاسمؒ اور ان کے بعد کا دور، چنانچہ تاریخ فرشتہ میں ہندوستان میں پہلی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھنے والے سلطان شہاب الدین غوری کا خط نقل کیا ہے جو انہوں نے شمالی ہند کے سب سے طاقتور حکمراں پِرتھوی راج کو لکھاتھا کہ تم سرحد، سندھ، پنجاب، بلوچستان میرے حوالہ کر دوتومیں دہلی واجمیر پر حملہ نہیں کروں گا اور اپنے مطالبے کے حق میں یہ دلیل دی تھی کہ یہ علاقہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے۔ اسی طرح بنگال (بنگلہ دیش) پر سات سو سالہ مسلم حکمرانی کے دورمیں مسلمانوں کی تعداد ۱۵؍۲۰فیصد سے زیادہ نہیں بڑھ سکی تھی، لیکن انگریز کے عین دور شباب میں حضرت سید احمد شہید بریلوی ؒ کے خلیفہ مولاناکرامت اللہ جونپوری ؒ نے دعوت کا کام کرکے بنگال میں تقریباً ایک کروڑ لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اس سے معلوم ہواکہ پاکستان کی اصل بنیاد بھی دعوت ہے نہ کہ دوقومی نظریہ۔ آج پاکستان اسی تضاد کے نتائج بھگت رہاہے کہ قائد اعظم نے دوقومی نظریہ (اسلام وکفرکی تفریق) کی بنیاد پر پاکستان بنایا اور بننے کے بعد اپنی ساری توانائی اور توجہ ایک قومی نظریہ (اسلام وکفر کی برابری) کے مطابق ڈھالنے پر لگا دی۔ یا د رکھیے !دعوت سے ہی دار کفردارالاسلام بنتاہے، نہ کہ کسی نظریہ سے۔
نازک حالات میں دعوت ہی نے ملت اسلامیہ کو سنبھالا
ہماری تاریخ کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ جب کبھی ملت پر نازک وقت آیا، اس وقت دین کے دوسرے شعبے یااپنی ادارے وجامعات کام نہیں آئے بلکہ دعوت ہی کے ذریعے حالات بدلے۔ مثلاً چھٹی صدی ہجری میں تاتاریوں کی یلغار کے وقت دینی اداروں، جامعات ،علما ومشائخ کی کمی نہیں تھی۔ صحرائے گوبی سے اٹھنے والی آندھی (تاتاری) نے عالم اسلام کو اس بری طرح تاراج وتباہ کیا کہ سمجھا جانے لگا، گویا اب اسلام کا خاتمہ ہے۔ ایسے نازک حالات میں اللہ کے چند مخلص بندوں نے خاموشی سے ان جنگجووجنگلی فاتحین کے دلوں پر دستک دی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، ان تک ایمان پہنچایا جس کے نتیجہ میں حالات نے ایک دم اسلام کے حق میں اس طرح پلٹا کھایا جس کا کوئی تصور نہیں کرسکتا تھا۔ بقول برطانوی پروفیسر اور علامہ اقبال کے استاذ آرنلڈ کے، جہاں مسلمانوں کی تلوار اور سارے وسائل ناکام ہوگئے، وہاں بے لوث دعوت نے مسلمانوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی اور فاتحین کی پوری نسل من حیث القوم اسلام کی آغوش میں آکر صدیوں تک کے لیے اسلام کی سب سے بڑی علمبردار اور محافظ بن گئی۔ اسی طرح ہندوستان میں دسویں صدی ہجری میں اسلام پر نازک وقت آیا جب برہمنوں کی ایک گہری سازش کے نتیجہ میں مغل امپائر کی سب سے زیادہ بلند حوصلہ اور طاقتور شخصیت اکبراعظم کودین الٰہی کے نام سے اسلام کے مقابلے پر لاکھڑاکیا گیا۔ وہ وقت برصغیر میں اسلام کے لیے نازک ترین وقت تھا۔ اللہ کے ایک مخلص بندہ (حضرت مجدد الف ثانیؒ ) کی خاموش دعوت نے ایسے حالات بدلے کہ اکبر اعظم کے تخت پر چوتھی پشت میں ایک ایسی شخصیت (اورنگزیب عالمگیر) جلوہ افروز ہوئی جنہیں عرب دنیاکے ممتاز عالم دین اور مفکر شیخ علی طنطاوی نے چھٹا خلیفہ راشد قرار دیا۔ اس عظیم انقلاب کا سہرا حضرت مجدد الف ثانی کی دعوت، خاص طور پر تحریر ی دعوت (مکتوبات) کے سر ہے۔ آپ نے اپنی تحریری دعوت کے ذریعے اکبر کے ارکان سلطنت وامراے دربار کے دلوں پر براہ راست دستک دی ۔ یہ آپ کی دعوتی کڑھن وکوشش کا کرشمہ تھا کہ اکبر کے اراکین سلطنت وامرا نے اس عظیم فتنہ کو اکبر کے شاہی محل میں دفن کردیا۔ غرض دعوت ہی سے ہر دور کے مسائل حل ہوئے۔
تمام مسائل کے حل کا نبوی طریقہ
یہاں سرسری نظر اس پرڈالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل کو کس طرح حل فرمایا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ایک طرف لٹے پٹے مہاجر تھے جو اللہ کے لیے اپناسب کچھ چھوڑ کر اور صرف جان بچاکر مدینہ پہنچے تھے۔ دوسری طرف مدینہ کے کاشتکار (انصار) تھے جن کا بال بال یہودیوں کے سودی قرضے میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ ؐنے مدینہ پہنچ کر چارکام کیے:
(۱)اللہ کی عبادت اور تعلیم وتربیت کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی۔
(۲) بے وسائل آنے والے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ایک مقامی (انصاری) اور ایک پردیسی (مہاجر)کے درمیان مواخات کے عنوان سے مضبوط رشتہ قائم کرکے ان پناہ گزین کے سارے مسائل ایک لمحہ میں حل فرمادیے۔
(۳) چاروں طرف خوف وہراس کا عالم تھا، مٹھی بھر مسلمان دنیابھر کے کفر کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی فضا ختم کرنے اور امن قائم کرنے کی خاطرمدینہ منورہ کے یہودیوں اورقبائل سے اپنے اپنے مذہب، شریعت اور معاشرت پر رہتے ہوئے مدینہ کے دفاع میں شرکت کرنے اور باہمی رواداری کے ساتھ رہنے اور آپسی مناقشات اور اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو تسلیم کرنے پر معاہدہ فرمایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے اور جو دنیاکا پہلاتحریری دستورہے۔ اسی طرح مدینہ کے اطراف میں کئی کئی سومیل کا سفر فرماکر مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے۔ کسی سے اس شرط پر معاہدہ ہواکہ جب مسلمانوں کے قافلے (عسکری وتجارتی) ان کے علاقوں سے گزریں تو ان کو اپنامہمان بنائیں۔ بعض سے اس شرط پر معاہدہ ہواکہ ان کے علاقہ سے اسلام کے دشمن گزریں تو ان کی مکمل اطلاع فراہم کریں، وغیرہ وغیرہ۔
(۴) اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری توجہ مسلمانوں کی تعلیم وتربیت پر مرکوز فرمائی۔ مسجد نبوی صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ مدرسہ، یونیورسٹی، خانقاہ، تربیت گاہ بھی تھی۔ مختلف اوقات میں تعلیم اور ذکر کے حلقے لگتے، پھر لوگ اپنے گھروں میں جاکر عورتوں اور بچوں کو تعلیم دیتے اور تربیت کرتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اہل مکہ کے ان قیدیوں کے لیے جو لکھناپڑھنا جانتے تھے، آپ نے رہائی کا یہ فدیہ مقرر کیا کہ دس مسلمان بچو ں کولکھنا پڑھنا سکھا دیں تو آزاد ہیں۔ سوچنے کی بات ہے جو قیدی اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے جذبہ سے آئے تھے، انہوں نے دین (قرآن وسنت) کی تعلیم دی ہوگی؟ بلکہ اس دور کی عصری تعلیم ہی دی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تعلیم وتربیت فرمائی کہ ہرصحابی رہتی دنیا تک کے لیے اعلیٰ آئیڈیل ونمونہ بن گیا۔ تاریخ شہادت پیش کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ (صحابہ کرامؓ) جماعت نے وقت آنے پر اُس دور کے ہر سیاسی، انتظامی، عسکری، معاشی مسئلے میں اور ہر ہر علم وفن میں کامل مہارت کا ثبوت دیا۔ ان میں ہر شخص داعی تھا۔ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی پہنچا، وہاں کے لوگوں کو اسلام اورایمان پہنچاکر ان کا معلم اور مقتدا بنا۔ گنتی کے چند صحابہ کے بارے میں کہاجاسکتاہے کہ وہ متخصص فی القرآن یا فی الفقہ یا فی القرأت تھے، لیکن صحابہ کرامؓ کی زندگی کا بغور مطالعہ بتاتاہے کہ ہر صحابئ رسول متخصص فی الدعوت تھا۔ وہ جہاں بھی گیا، ہزاروں لاکھوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفرازکرگیا۔ اگرمسلمان داعی نہ ہوتو اس کا ایمان اور اسلام اتنا کمزور ہوگا کہ وہ نامساعد حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔
داعی کی مثال ایک تاجر کی سی ہے۔ جس طرح تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے گاہک کی ہرطرح کی بدتہذیبی، سختی اور بداخلاقی برداشت کرکے نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتاہے، اسی طرح داعی بھی مدعوین کی ہر طر ح کی سختی، درشتی اور بداخلاقی کو نظر انداز کرکے اخلاق کریمانہ اور ہمدردی سے اپنی بات پہنچاتاہے۔ تاجر ہر وقت گاہک کے پسندوناپسند، مزاج ونفسیات، رضا وخوشی اور دلجوئی کی فکر میں رہتاہے۔ اگر تاجر دیکھتا ہے کہ گاہک اس کی دکان میں نہیں آرہاہے تو وہ یہ نہیں کہتاکہ میری بلاسے، اگر خریدنا ہوگا تو خود آئے گا، بلکہ وہ گاہک کی پسند کے مطابق دکان کواور خودکوڈھالتاہے۔ اگر کسی جگہ دکان نہیں چل رہی تو سوچتاہے شاید عملہ نا اہل ہے ، عملہ بدلتا ہے۔ پھربھی نہ چلے تو سوچتاہے شاید دکان کا ڈیکوریشن اور فرنیچر (سجاوٹ) گاہک کو ترغیب دلانے میں ناکام ہے۔ وہ ڈیکوریشن بدلتاہے۔ پھربھی گاہک نہ آئے تو سوچتاہے کہ شاید اس جگہ کپڑے کے بجائے اناج کی دکان چلے گی۔ دکان کا سامان بدلتاہے اور کبھی دکان کی جگہ ہی تبدیل کر دیتاہے۔ اپنے مال کی ایڈوٹائزنگ کے لیے جدید تشہیری طریقہ اختیار کرتاہے، نہایت صبر وتحمل اور بردباری سے محنت کیے جاتاہے، یہاں تک کہ دکان چل پڑتی ہے۔ افسوس! ہمارا ذہن ودماغ تجارت میں تو نت نئے تجربات کی تلاش میں سرگرداں رہتاہے، لیکن جب دعوت یاانسانیت تک دین وایمان پہنچانے کا مرحلہ سامنے آتاہے تو اکابر اکابر اور اسلاف اسلاف کے نا م پر صدیوں پرانے اسلوب، زبان ولہجہ،طریقۂ کار ہی دہراتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا دعوت دینے کاطریقۂ کار مخاطب کی ذہنی سطح ،مزاج ونفسیات ،زبان واسلوب کے مطابق ہے یا نہیں؟ہم خود کو دھوکہ میں رکھتے ہیں کہ آخر ت میں ہمارے نامۂ اعمال میں اتنے کروڑ اتنے ارب نیکیاں جمع ہو رہی ہیں ،خواہ ہم اپنے طرز عمل اور بداخلاقی سے لوگوں کو اسلام ایمان سے بدظن ومتوحش ومتنفر ہی کررہے ہوں۔
دعوت کی عظمت اورداعی کے اوصاف
دعوت درحقیقت ایمان(اللہ کو ماننے )کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا تھا، اسے اسی وقت ایمان کی دعوت کا فریضہ سونپ دیتے۔ صدیق اکبرؓ نے ایمان لاتے ہی ایمان کی دعوت دینی شروع کی اور محنت کرکے اسی دن کی شام تک چھ نئے لوگوں کو ایمان پر لے آئے جن میں کئی عشرۂ مبشرہ میں سے بنے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایمان قبول کرتے ہی حرم میں پہنچ کر علانیہ اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ایمان کی دعوت دی۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہؓ نے جب ایمان قبول کیا تو کلمہ شہادت کے اقرار کے بعدحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل اشہد اللہ واشہد من حضر انی مسلمٌ مجاہد مہاجر (حیاۃ الصحابہ) میں اللہ کو اور حاضرین کو گواہ بناکر کہتاہوں کہ میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں، یعنی میں نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ ایمان پھیلانے کی محنت کرنے والا اور اایمان واسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ نے والا (قربانی کرنے والاہوں) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو مسلمان بنانے کے ساتھ ہی داعی اور دعوت کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا بھی بنادیتے تھے۔ یہی اصل کار نبوت، طریق نبوت اور سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو شخص بھی ایمان لاتا، اسے اسی کے قبیلہ اور قوم میں ایمان کاداعی بناکر روانہ فرماتے۔ اس طرح بہت سارے افراد کی دعوت پر ان کا پورا قبیلہ یا قبیلہ کے بہت سے افراد مسلمان ہوجاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، مثلاً عرب کے قبائل کا لباس تقریباً یکساں ہوتا تھا۔ نام بھی تقریباً سارے صحابہ کے اسلام سے پہلے کے ہیں۔ ہاں اگر کسی کے نام میں شرک کی بو آتی یا اس کے کوئی نامناستب معنی ہوتے تو اسے آپ تبدیل فرمادیا کرتے تھے، لیکن آج مثلاً کوئی یہودی یا عیسائی شخص میرے پا س آکر مسلمان ہوتو میں اس میں ایمانی صفات پیدا کرنے یا داعی بنانے کے بجائے ظاہر پر زیادہ توجہ دوں گا۔ سب سے پہلے نام بدلوں گا، پھر اس کا لباس، حتیٰ کہ ٹوپی عمامہ پہناکر اس کو اس کے اپنے معاشرے سے کاٹ دوں گا۔ اب وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ اپنے معاشرے میں جاکر دین کی دعوت دے سکے۔ اس مسئلہ پر بھی غورکرنے کی ضرورت ہے۔
ہر داعی گویا براہ راست اللہ کی طرف سے پیغامبر ہوتاہے، اس لیے وہ خداکے نمائندے کی حیثیت سے بلند سطح سے بات کرتاہے۔ داعی کے لیے یہ بلند ترین مرتبہ حاصل ہونے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ ہر وقت خداکی عظمت، بڑائی اور کبریائی کااستحضار ہو۔ ہر نبی کا پہلا بول ہی اللہ اکبر رہا۔ اگر چہ قرآن کی پہلی آیت پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی مگر پڑھایا کیا؟ اللہ کی عظمت اور دعوت پڑھائی، چنانچہ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی، وہ ہے: یا یھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے گدڑی میں لپٹے ہوئے! اٹھیے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔
دوسری بات داعی کی نظروں میں دنیا کی بے ثباتی اور بے حیثیتی ہے۔ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی حیثیت اور قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی توکسی منکر خداکو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا۔ داعی کے دل میں دنیا کی بے حیثیتی کا بیٹھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ اس کی دعوت بے جان ہوگی۔ ایک بار بندہ حکومت مراکش کی دعوت پر داربیضہ (Casa Blanka) اسلامی دعوت کا نفرنس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ ہوائی جہاز میں میری سیٹ کے ساتھ ایک نوجوان کی سیٹ تھی۔ جب جہاز نے اُڑان بھری اور زمین سے بارہ چودہ ہزار فٹ بلند ہو ا اور میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھاتو لندن شہر کی بڑی بڑی شاہراہیں ایسے نظر آئیں گویا کسی نے کالی لکیر کھینچ دی ہو اور لندن کی عظیم الشان بڑی بڑی عمارتیں جنہیں دیکھ کر دل مرعوب ہوتا تھا اور دل میں ان کی عظمت اور شان وشوکت بیٹھتی تھی، ایسی حقیر، معمولی اور چھوٹی چھوٹی نظر آرہی تھیں گویا کسی نے سگریٹ یا ماچس کی بہت سی ڈبیاں ایک دوسرے پر رکھ دی ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ذرانیچے دیکھیے، لندن شہر اور اس کی شاندار عمارتیں کتنی حقیر اور بے حیثیت نظر آرہی ہیں۔ سبب یہ ہے کہ ہم محض جسمانی طور پر زمین سے چند ہزار فٹ اُوپر آگئے۔ اگر خداہمیں روحانی سربلندی نصیب فرمادے تو دنیا کی ان چیزوں کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی!
تیسری چیز داعی کا اپنے دعوت کے معاملے میں بے لوث ہوناہے کہ وہ اپنی کوششوں اور قربانیوں پر مخلوق اور انسانوں سے کچھ نہیں چاہتا۔ ہرنبی کی بنیاد یہی ہوتی تھی، ما اسئلکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العٰلمین، اے لوگو! ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں جو چاہیے، اللہ سے لیں گے۔ یہ تین صفات داعی کو نہایت ممتاز حیثیت عطاکر دیتی ہیں اور بلند ترین مقام پر فائز کردیتی ہیں۔ پھر اللہ اپنی غیبی طاقت اس کے ساتھ کردیتاہے۔ وہ اللہ کا محبوب ہوتاہے۔ ظاہرہے جو اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑ رہا ہو، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پیارا کون ہو سکتا ہے! ظاہر ہے پھر اس کا مقام یہ ہوتاہے کہ ایک سپرپاور (سلطنت ایران) کا فرمانرواداعی (پیغمبراسلام)کے دعوت کے خط کو چاک کردیتاہے تو داعی فرماتاہے کہ اس نے ہمارا دعوت نامہ نہیں، اپنا ملک چاک کرکے ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور یہ منظر دنیادیکھتی ہے کہ چندہی سالوں میں اس کی عظیم سلطنت پارہ پا رہ ہوکر نیست نابود ہوجاتی ہے۔
ذہنوں پر سیاست کے غلبہ کے مضمرات
ہم سے ایک بڑی غلطی عصر حاضر میں یہ ہورہی ہے کہ ہمارا ذہن داعیانہ کے بجائے سیاسی بن گیاہے۔ گزشتہ صدی میں عالم اسلام پر مغرب کے سیاسی غلبے کے ردعمل کے طور پر ہمارے بعض مفکرین کو یہ مغالطہ ہواکہ مسلمانوں میں باطل (مغربی تمدن، فکروفلسفہ اور کمیونزم) یورپ وروس کے سیاسی تفوق وغلبہ کے سبب پھیل رہاہے۔ اگر ہمارے پاس بھی مستحکم سیاسی حکومت ہوتی تو ہم اسی طرح اسلام پھیلاتے۔ اس طرح ان کا ذہن دعوت کے بجائے سیاست، ایمان وعمل کے بجائے ریاست کے حصول کی طرف لگ گیا۔ اسلام کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کبھی ریاست وحکومت یاسیاسی طاقت سے نہیں پھیلا بلکہ اکثر سیاسی شکست اور حکومتی عدم استحکام کے زمانے میں تیزی سے پھیلاہے۔ مثلاًتاتاریوں کی یلغار عالم اسلام کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ تاتاری لشکروں نے پورے عالم اسلام کو تہہ وبالا کردیاتھا، ہر شہرلاشوں سے پٹاپڑا تھا، ہرجگہ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر اونچے اونچے منارے سجائے گئے تھے۔ تمام مؤرخین اسلام کے خاتمے کی پیشین گوئی کررہے تھے۔ ایسے مایوس کن حالات میں اللہ کے کچھ بندوں نے انھی سفاک قاتلوں (تاتاریوں)کو دعوت دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک دن میں ان کے لاکھوں گھرانے مسلمان ہوئے اور پوری تاتاری قوم من حیث القوم حلقہ بگوشِ اسلام ہوگئی۔ غرض اس سیاسی عدم استحکام کے دور میں اس طرح اسلام پھیلاکہ تاریخ میں اس کی نظیر نہ پانچ سو سال پہلے ملتی ہے نہ پانچ سو سال بعد تک۔ آج پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کی پسپائی، شکست، کم ہمتی،ذلت وغلامی کا وہی سماں ہے جو تاتاریوں کے حملے کے وقت تھا۔ آج اسلام کے خلاف شرانگیز پروپیگنڈے نے ہر مسلمان کو مجرم بناکر رکھ دیاہے۔ اس کے باوجود آج پھر دنیامیں اسی طرح اسلام پھیل رہاہے جیسا تاتاریوں کے یلغار کے بعد پھیلا تھا۔ خاص طور پر مغرب (امریکہ، یورپ) میں اس تیزی وسرعت کے ساتھ اسلام پھیل رہاہے کہ اس نے عالمی کفر کے سرغنوں کو حیران وپریشان کردیا ہے ،جبکہ ہمارے پاس دنیا بھر میں دعوت کا کوئی خاص نظم ہے نہ کوشش، لوگ ازخود ذاتی مطالعہ وتفکر سے یاکتابیں پڑھ کر اسلام کی طرف آرہے ہیں۔ اگر ہم دعوت کے فریضہ پر کھڑے ہوجائیں تو آج پھر تاتاریوں کے دور کی طرح یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں حیران کن نتائج سامنے آسکتے ہیں اور تاتاریوں کی طرح اسلام کو دنیا سے مٹانے کا جذبہ رکھنے والی اقوام ، اسلام کی پاسبان بن سکتی ہیں۔
اشاعت اسلام کی راہ میں سب سے بڑ ی رکاوٹ
عصر حاضر میں ہمارے بعض مفکرین کی تحریروں کے سبب ہمارے ذہنوں پر دعوت کے بجائے سیاست سوار ہوگئی ہے۔ اس سیاسی ذہن نے انسانیت کے متعلق ہمارا نقطۂ نظر تبدیل کردیاہے اور ہمیں اقوام عالم کا حریف بنا دیا ہے۔ ہم نے خود کو محتسب اقوام یادنیا بھر کی قوموں کے لیے خدائی فوجدار سمجھ لیاہے، جبکہ قرآن وحدیث کی روسے اقوام عالم کے لیے ہماری پوزیشن ناصح وامین یعنی اقوام عالم تک ایمان واسلام کی امانت بلاکم وکاست پہنچانے والے اور انسانیت کے سچے بہی خواہ اور خیر خواہ کی ہے۔ جیسے کوئی سچا ڈاکٹر خیر خواہی کی حد تک اپنے مریض کا خدمت گار ہوتاہے، اسی طرح داعی انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ وخادم ہوتاہے۔ حضرت مدنی ؒ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات انبیاء ؑ سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ ان کا حال اس بات کا ساہوتا تھا جس کا اکلوتا لڑکا آگ کے شعلہ میں گرا چاہتاہو اور وہ بے قرار ہو کر ہر حال میں اسے بچانے کی کوشش کررہاہو۔ دعوت انسانیت کی خیر خواہ بناتی ہے اور سیاست نفرت پیداکرتی ہے۔ حضرت مدنی ؒ سمجھتے تھے کہ دوقومی نظریے سے برصغیر میں نفرت کا وہ طوفان اٹھے گا کہ برصغیر کی اقوام میں اسلام کی اشاعت دشوار تر ہوجائے گی۔ دوقومی نظریہ کی تفریق ونفرت سے پہلے صرف کلکتہ کی مسجد ناخدامیں روزانہ تقریباً سوآدمی آکر مسلمان ہوتے تھے،اسلام خاموشی سے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنارہاتھا۔ اس سیاسی نفرت نے ہندوکو متحدومستحکم کرکے برہمن کے شکنجے کو پورے بھارت پر مضبوط کردیا، برہمن جس کی ہزار ہا سال سے عالمی طور پر کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ آج ایک عالمی طاقت بن گیا ہے، حتیٰ کہ وہ عالمی صہیونی وصلیبی طاقتوں سے مل کر اسلام کو دنیا سے مٹانے کا منصوبہ بنارہاہے۔ سیاست نے برصغیر میں ہندو کو عظیم طاقت بنادیا، ورنہ مذہب کے اعتبار سے اس سے زیادہ بودا اور کمزور کوئی مذہب نہیں تھا۔ غرض عصرحاضرمیں اسلام کی اشاعت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سیاسی تعصبات ونفرت ہے۔ پنڈت جواہر لعل نہرو نے اپنی کتاب ’’ڈسکوری آف انڈیا‘‘ میں لکھاہے کہ ہندوستان میں مذہب کی تبدیلی پر اگر کوئی اعتراض کرتاہے تو وہ سیاسی سبب سے ہوتاہے نہ کہ مذہبی سبب سے۔
دعوت کی بنیادی ضرورت
دعوت کے لیے بنیادی ضرورت حالات کا نارمل رکھناہے۔ قرآن نے حالات کو پرامن نارمل رکھنے کے لیے جگہ جگہ صبر اور اعراض کی تعلیم دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشید گی کم کرنے اور باہمی حالات کو نارمل بنانے کی خاطر حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی انتہائی غلط قسم کی اشتعال انگیز یک طرفہ شرائط بھی منظور فرمالی تھیں جس کے نتیجہ میں وہ صلح نامہ فتح مبین بن گیا۔ قرآن وسیرت سے ہمیں یہی سبق ملتاہے کہ ہر قوم پر عمل وکردار اور دعوت کے ذریعہ اتمام حجت کیاجائے۔ ان تمام مراحل کے بعد آخری مرحلہ قتال کا آتاہے ۔ آج ہم دعوت چھوڑکر ایک جامد نسلی گروہ بن کر رہ گئے ہیں، جیسے کسی گڑھے میں پانی ٹھہر کر آہستہ آہستہ متعفن بدبودار اور گندا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس میں نیاپانی شامل ہوتارہے، وہ چشمہ صافی رہتاہے۔ ضرورت ہے کہ اسلام کے چشمہ صافی میں ہرزمانہ میں ہرآن نیاخون شامل ہوتارہے تاکہ کثافت دور ہوتی رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کے علمبردار اور اس کے پھیلانے والے ہر دور میں نومسلم ہی رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرامؓ بھی نو مسلم تھے اور ساتویں صدی ہجری کے تاتاری (اتراک بھی) اور بیسویں صدی کے تبلیغ جماعت کے میواتی بھی ایک طرح کے نو مسلم تھے۔ جس طرح تیرہویں صدی عیسوی کے تاتاریوں نے سمرقند سے حلب تک تما م عالم اسلام کی مساجد تباہ کرکے کھنڈر بنادی تھیں، پھر دعوت کی بر کت سے انہی کی اولاد نے ان تما م مساجد کو نہ صرف تعمیر کیا بلکہ سجدوں سے آباد بھی کیا،آج بھی ہماری تمام مشکلات اور مصائب کا حل صرف ایک ہے۔ وہ ہے حالات کو معتدل رکھ کر اقوام عالم سے الجھے بغیر ان کو اسلام اورایمان کی دعوت دی جائے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام دعوت کے معاملے میں اجتہادی کوتاہی سے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دئے گئے تھے، آج پوری ملت اسلامیہ دعوت فراموشی کے جرم میں ہر قسم کے مسائل کے شکنجے میں اس طرح جکڑدی گئی ہے کہ ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں کہ دوسرا پیداہو جاتاہے۔
دین پھیلانے کی محنت ہی امت مسلمہ کو متحداور یکجا کرسکتی ہے
آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ باہمی تشتت وافتراق ہے۔ ہماری پوری تاریخ شاہد ہے کہ یہ امت صرف دعوت وجہاد پر ہی جمع ومتحد ہوسکتی ہے نہ کہ کسی مسلک پر، کیونکہ پوری امت نہ حنفی بن سکتی ہے نہ مالکی نہ شافعی نہ حنبلی، نہ امت کسی ایک بزرگ کی بیعت پر اور تصوف کے کسی خاص سلسلے پر متفق ہوسکتی ہے، نہ کسی ایک جامعہ یاادارہ مثلاً جامعہ ازہر یا دیوبندپرمتحد ہوسکتی ہے۔ آج بھی کھلی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں تبلیغ کا کام شروع ہوا، پوری امت ایک جگہ جمع ہوگئی۔ مثلاً تبلیغی جماعت (جس کا کام دعوت کے بجائے تذکیر ہے) کے اجتماعات میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہر مذہب کے لوگ اور تصوف کے ہر سلسلے کے افراد اور ہر نسل کے ہزار ہا افراد جمع ملیں گے، مثلاً سوڈانی ،نائجیرین، اردنی، سعودی، انڈونیشی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جہاد افغانستان میں سعودی، شامی، مصری، یمنی، الجزائری، مراکشی، لیبی، افریقی ،یورپی، امریکی، چینی، چیچن، البانی، ترکستانی غرض کہ ہر ملک ونسل کے مسلمانوں نے اپناحصہ ڈالا، جبکہ دعوت وجہاد کے علاوہ دین کے دوسرے شعبوں میں صرف قومی نسلی جھلک ہی نظر آئے گی۔
(جاری)
کرکٹ اور گروہی نرگسیت
پروفیسر ابن حسن
کہا جاتا ہے کہ ادب میں المیہ اور رزمیہ سب سے ارفع اصناف سخن ہیں اور پھکڑ ڈرامہ farce اصناف کی درجہ بندی میں سب سے نیچے ہے۔ رزمیے کا آغاز تاریخی طور پر دو موثر اور وسیع قوتوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے شاعر اعلیٰ مضمون کے بیان کے لیے عام زندگی سے ارفع الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔اپنی جگہ یہ شاعرانہ کمال ہے۔ اس کو پڑھنا جمالیاتی حظ ہے، لیکن جب اسی قبیل کے ادبی حربوں کو کسی ایسے واقعے کے لیے مستعار لیا جائے جو عامیانہ، گھٹیا اور سطحی ہو تو اسے بیہودگی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایسے میں الفاظ گویا سچائی کی بجائے منافقت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس بے معنی ڈرامے کے کردار عظیم تاریخی ہستیوں کی بجائے مسخرے، جوکر، بازی گر، ٹھگ، اٹھائی گیرے، نوسر باز، سیہلے باز ہی ہو سکتے ہیں۔
اس طرح کا بے معنی ڈرامہ ہر روز ہمارے سامنے رچا یاجاتا ہے، لیکن جن دنوں کرکٹ میچ ہو رہا ہو، اس نوٹنکی کے رنگ ہی اور ہوتے ہیں۔ اخبارات اور ٹیلی وژن کے پروگراموں میں بے شمار ’ماہرین‘ شاندار ڈسکورس کے نمونے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ جی کڑا کر کے چند منٹ ان کی گفتگو سنیں تو اس سے ایک بات ضرور ثابت ہو گی کہ انسان کو ایسی قوتِ گفتار عطا ہوئی ہے کہ وہ بغیر کسی موضوع اور بغیر کسی مواد کے کئی کئی گھنٹے بول سکتا ہے۔ اس گفتگو میں استعمال ہونے والے چند الفاظ ملاحظہ ہوں: ’پنچہ آزمائی‘۔ ’دو قوتوں کا ٹکراؤ‘۔ ’ایشیا اور یورپ کی جنگ‘۔ ’کرکٹ کی حکمرانی کے لیے معرکہ‘۔’ فلاں ملک کے شیر‘۔ ’ فتح کا تاج‘۔
پھر اس عظیم رزمیے کے نتائج کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں: ’شیروں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا‘۔ ’انگریزباؤلروں کا بھرکس نکال دیا‘۔ فلاں کی پٹائی ‘۔’ریت کی دیوار‘۔ ’فیلڈنگ کا قلعہ‘۔ اس طرح کے الفاظ کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان’عظیم دانشوروں ‘نے اپنے کمالِِ تخیل سے پیدا کی ہے۔
اگر میچ میں کامیابی (اسے عام طور پر ’فتح‘ کہا جاتا ہے) ملی ہے تو رزمیے کا farce بننا اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو تو رزمیہ المیے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ جیسے کسی بھی ملک کی فوج کو کبھی بھی شکست نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نا قابل فہم عوامل یا تقدیر کی ستم ظریفی سے ’فتح‘ میسر نہیں ہو پاتی۔ (یاد رہے کہ ایسا کبھی نہیں کہا جاتا کہ ہماری فوج کو ’شکست‘ ہوئی)۔ کرکٹ ٹیم اس لیے ’فتح‘ سے محروم رہتی ہے کہ کسی کلموہے امپائر نے بے ایمانی کی، یا شومئی قسمت سے کوئی کیچ چھوٹ گیا، دنیا کا عظیم ترین بیٹسمین آؤٹ آف فارم تھا، یا اس کا ناقابل یقین کیچ پکڑ لیا گیا وغیرہ، وغیرہ۔ اب دل کو تسلی دینے کے لیے بڑا عمدہ جملہ موجود ہے کہ ’میچ فکس تھا‘۔
یہ ثقافتی ارتقا کی تصدیق بھی ہے کہ آج کے دور میں اگر رزمیہ لکھا جائے تو یہ farce ہی ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دھوکا دینے اور اپنے محدودات چھپانے کے لیے اپنے ماضی سے نعرے اور الفاظ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس طرح کھڑا کیا جانے والا رزمیہ بندروں کا تماشہ لگے گا۔
ایسا کیا ہے کہ کسی قوم کا سوادِ اعظم کرکٹ میچ میں کامیابی یا ناکامی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنالے، ناکامی پر پہلے سے بے روح چہرے اور مکروہ شکل اختیار کر لیں، کامیابی پر ہلڑ بازی کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے، ڈھول بجائے جائیں اور دیگیں چولھوں پر چڑھ جائیں گویا بیت المقدس فتح ہو گیا ہو!
اس سماجی اور ثقافتی مظہر کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ حکمران طبقے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے تماشوں کو ہوا دیتے ہیں۔ لوگ اپنے مسائل بھول کر ہلے گلے کو کتھارسس کا ذریعہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ فلمی ستارے، کھیلوں کے ستارے، مشہور ہستیاں وغیرہ طبقات کے مابین تضاد کو کند کرنے کا بہت آسان اور مروج ذریعہ ہیں۔ اس طرح یہ ایک طرح کا مجہول انحصاری پن ہے جس میں فرد اپنی شخصیت کو کسی اور کے سہا رے کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے نرگسیت میں میرا خاندان، میرا حسن و جمال، میری عقل، میرا گھر ، وغیرہ جیسے ہزاروں ہیولے جنم لے لیتے ہیں، اسی طرح میرا ہیرو، میرا فیورٹ سٹار، فرد کی اپنے آپ کی کسی اور میں projection ہے۔
ایرک فرام کا کہنا ہے کہ ’’جب گروہی نرگسیت کا مطمح نظر فرد نہیں بلکہ وہ گروہ ہو جس سے فرد کا تعلق ہے تویہ دعویٰ کہ میرا ملک، (یا میری قومیت، مذہب وغیرہ ) سب سے زیادہ زبردست اور عمدہ ہے، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ امن پسند وغیرہ ہے تو یہ قطعاً احمقانہ پن نہیں لگتا۔ اس کے برعکس یہ حب الوطنی ، ایمان یا وفاداری کا اظہار لگتا ہے۔ [فرد کو ] لگتا ہے کہ یہ عقل پر مبنی رائے ہے کیونکہ اس گروہ کے بہت سے افراد اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اتفاقِ رائے واہمے کو حقیقت کا روپ دے دیتا ہے کیونکہ اکثر کی رائے میں جس چیز پر بہت سے لوگ یقین رکھتے ہوں، لازماً درست ہو گی۔ درست ہونے کا معیار تعقل یا ناقدانہ جائزہ نہیں۔ (Anatomy of Human Destructiveness, p 203)
آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ’’بیمار ذہن کا فرد اپنے جیسے دوسرے افراد کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہے۔ تمام معاشرت اس سمت بھاگی چلی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عام فرد وہ اکلاپا اور تنہائی محسوس نہیں کرتا جو وہ شخص محسوس کرتا ہے جس کادماغی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا ہو۔‘‘ (ایضاً)
کیا افراد، تنظیمیں، قومیتی اور نسلی گروہ، حتیٰ کہ پوری قوم کو نرگسیت کا شکار کہا جا سکتا ہے؟ (ہم اس کے لیے گروہی نرگسیت کی اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں)۔ گروہ کی بتدریج ارتقا پذیر ساخت اپنی معاشرتی اور ثقافتی زندگی میں بے شمار عوامل سے اثر پذیر ہو کر فرد کو اپنے میں گویا تحلیل کر لیتی ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے کی خامی یہی ہے کہ یہ فرد سے خود اس کے وجود کا معنی تک چھین لیتا ہے اور گروہ پوری طرح سے اُسے اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اس طرح کا اجتماعی شعور تعقل کا اظہار نہیں رہتا۔ حقیقی رویے یا خیالی دنیا fantasy میں تعریف و تحسین کی شدید خواہش، خوشامد پسندی یا انسانی ہمدردی کا فقدان اسی رویے کو فاشزم کی شکل دیتا ہے۔ گروہ یا اس کے افراد بطور گروہ یا بطور فرد اس تعلق کی بنا پر اپنی شان و شوکت اور اہمیت کو مبالغہ آمیز انداز سے دیکھتے ہیں۔یہی مبالغہ گروہ کی کامیابیوں کو جھوٹ کی حد تک چمک دمک دیتا ہے۔ اسی بنا پر افراد یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کامیابی کے بھی انہیں برتر جانا جائے۔ (حکمران اسی لیے کرکٹ ٹیم جیتے یا نہ جیتے، اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کرتے ہیں)۔ افراد گروہ سے اجتماعی وابستگی کی بنا پر لامحدود کامیابی کے خواب خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔انہیں یہ سودا ہو جاتا ہے کہ وہ لامحدود اور مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں۔ اسی خواب وخیال کی دنیا میں وہ دنیا پر تسلط اور غلبے کے خواب دیکھتے ہیں۔ کرکٹ سے وابستہ مال و دولت کی بہتات نوجوانوں میں اس واہمے کو اور تقویت دیتی ہے۔ اجتماعی نرگسیت فرد کو اس واہمے کی طرف لے جاتی ہے کہ اسے اعلیٰ درجے کے گروہوں اور ارفع رتبے کے اشخاص سے جوڑا جائے۔ اس لیے انہیں چنیدہ لوگوں کی طرح تحسین و تعریف بھی دی جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ان کی یہ خواہش اور بھی بیمارانہ ہو جاتی ہے کہ دوسرے ان کے حوالے سے ڈر اور خوف محسوس کریں۔ تیز باولروں کے لیے اس طرح کی خوفناک امیجری اسی لیے استعمال ہوتی ہے۔
اس طرح کے افراد غیر معقول ترجیحی سلوک کی توقع رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ ان کی توقعات کی مکمل تابع فرمانی کریں۔ اسی لیے وہ اپنی غلطیوں اور جرائم کی کوئی ذمے داری قبول نہیں کرتے۔ (alloplastic defenses)۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کرکٹرز سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اسے کسی ناہنجار کی ’سازش‘ کہا جاتا ہے اور سارا میڈیا ان کا دفاع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ان کے جنسی اسکینڈل میں قصوروار ہمیشہ خاتون ہی ہوتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا افراد دوسروں کے جذبات اور احساسات کی قطعاً پروا نہیں کرتے۔ اس لیے وسیع پیمانے پر منظم جرائم ان میں کسی قسم کی ضمیر کی خلش پیدا نہیں کر سکتے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کرکٹرز میں ’ملک کانام روشن‘ کرنے کا جذبہ میچ فکسنگ کے ذریعے پیسہ کمانے کی ہوس میں بدل جاتا ہے۔ اگر کبھی یہ قانون کے شکنجے میں آ بھی جائیں تو ان کا ردِ عمل غصے اور بدمزاجی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔
ان وجوہات کی بنا پر کرکٹ کے شیدائی قطعاً نہیں پہچان سکتے کہ کہ وہ کرکٹ کے حسن پر فریفتہ ہو کر خود اپنی عقل اور شکل دونوں کو بگاڑ چکے ہیں۔ کرکٹ پر شور و غوغا کر کے آسمان سر پر اٹھا لینا جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات کو مسخ کرنا ہے۔ یہ قابلِ رحم ذہنی بانجھ پن اورثقافتی گھٹیا پن ہے جس میں خود مسرت، حظ، لطف کا حصول مجہولیت کے درجے تک آ جاتا ہے۔ شخصیت کا ارتقا اس کا زوال اور تذلیل ہے۔ وہ اس لیے کہ ثقافتی وجود فرد کی ذات کی تکمیل کی بجائے اسے بے رحمی سے خالی کر کے اس میں ہر وہ چیز بھر دیتا ہے جو خود اس کے وجود کی تردید ہے۔ پوری قوم علمی، اخلاقی اور ثقافتی اعتبار سے ا س قدر گر جاتی ہے کہ اچھائی اور برائی، اعلیٰ ذوق اور بیہودگی، پھکڑ پن اور سنجیدگی، جھوٹ اور سچ میں فرق مٹ جاتا ہے۔اسی لیے کرکٹ ثقافتی زوال کی بہت بڑی نشانی ہے۔
تاریخ کی درستی: بھٹو سے فیض تک
چوہدری محمد یوسف ایڈووکیٹ
سلمان تاثیر کے قتل کے بعد، توہین رسالت کیس کو تبدیل کرنے کے بارے میں حکومت پر بین الاقوامی دباؤ ختم ہوا، چنانچہ کم و بیش ہر روز زعیمان مملکت قانون میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنے کا یقین دلاتے رہے۔ رحمان ملک کی یقین دہانی کو تو کوئی مانتا نہیں تھا۔ آخر کار وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے بھرے اجلاس میں یقین دلایا۔ اس کے باوجود پبلک احتجاج جاری رہا۔ اسی اثنا میں ریمنڈ ڈیوس کا قصہ شروع ہو گیا۔ حکومت پھر دباؤ میں آگئی۔ دو اڑھائی مہینے تک دباؤ چلتا رہا۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں ہی نہیں، فوج، آئی ایس آئی اور عدلیہ نے بھی ڈیوس کی رہائی اور پاکستان سے رخصتی میں بھر پور حصہ ڈالا۔ مقتولوں کے ورثا لا پتہ ہیں۔ لگتا ہے کہ سینکڑوں دیگر لا پتہ لوگوں میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ابھی ان کی تلاش اور جستجو دم نہیں توڑ پائی تھی کہ مجید نظامی کے بقول، مرد حر نہ کہ مردِ حریت جناب آصف علی زرداری نے تاریخ کی درستی کے نام پر ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اس کی رو سے وہ بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دلوانا چاہتے ہیں۔ اس ریفرنس کی پیروی کا کریڈٹ بھی اس شخص کو گیا جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس نے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائی تقسیم کی تھی۔ کریڈٹ کی تقسیم حاکم مطلق کے ہاتھ میں ہے۔
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے
کمال ڈرامہ ہوا۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس کی پیروی کے لیے وفاقی وزیر قانون پیش ہوگئے۔ یوں جیسے جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے اپنا لائسنس وکالت خود وزارت کی خاطر معطل کرایا ہوا ہے۔ عدالت نے وزیر صاحب کو پیروی کی اجازت کے لیے وزارت سے مستعفی ہونے کو کہا تو فوراً ہی استعفا پیش کر دیا۔ نالائقی یا ہشیاری کی حد دیکھیے کہ وزیر قانون چیف جسٹس کو استعفا پیش کر رہے ہیں۔ در اصل ڈرامہ کیا جا رہا تھا۔ میڈیا میں سٹوری بنانا مقصود تھا۔ صدرِ مملکت کی نظر میں نمبر بنائے جا رہے تھے۔ کچھ حرج نہیں، نمبر گیم جاری رہے۔ تاریخ کی درستی کا عمل شروع ہو لے، اس عمل کے دوران نمبر گیم الٹنے کا سلسلہ شروع ہو گاتو پھر کسے ہوش رہے گا۔ اس گیم کے حصہ دار کنتی بھول جائیں گے۔ بہر حال تاریخ کی درستی کا عمل تو اسی روز شروع ہو گیا تھا جب افتخار حمد چوہدری نے چھ وردی پوش جرنیلوں (بشمول جنرل کیانی) کی جانب سے مستعفی ہونے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اڑھائی سال تک، پاکستان کے گلی کوچوں میں جب یہ نعرے لگتے تھے، ’’کرنل جنرل ۔ ۔ بے غیرت‘‘ تو یہ تاریخ کے پہیے کو الٹا پھیرنے کی کاوش ہی تو تھی۔ نتیجتاً یہ عوام کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ ایک فیصلہ تھا جس نے ساٹھ سالہ نظریہ ضرورت کو لنگوٹی چھوڑے بغیر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہ عوام کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں تھا۔ ابھی بہت سے فیصلے باقی ہیں۔ ہم جناب زرداری کے ریفرنس کا خیر مقدم کریں گے۔ ریفرنس پر فنی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرناہے، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ فیصلہ جو بھی ہو گا، حکومت تو صرف اس کا احترام کرے گی، مگر عوام فیصلے کو اپنی پراپرٹی کے طور پر دل و جان سے عزیز تر جانیں گے۔
اس مرحلہ میں ہماری گذارش یہ ہے کہ تاریخ کی درستی کا عمل بڑا احسن ہے، مگر کسی ترتیب سے شروع ہو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ زمانی ترتیب سے ریمنڈ ڈیوس کیس ۲۰۱۱ء کا کیس ہے۔ یہ تازہ ترین کیس ہے۔ اس کے بر عکس راولپنڈی سازش کیس ۱۹۵۱ء ہماری ملکی تاریخ کا پہلا کیس تھا۔ کوئی بھی ترتیب اختیار کی جا سکتی ہے۔ پہلے کیس سے شروع کریں یا تازہ ترین کیس سے، یہ حکومت کی مرضی ہے۔ چلیے اگر درستی کا عمل بھٹو کیس ہی سے کرنا ہو تو اس پر بھی اعتراض نہیں، مگر اس کیس کو مرکزی کیس مان لیا جائے اور اس سے پیچھے اور آگے، تقدیمی و تاخیری ترتیب بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تاریخ تو اپنا عمل شروع کر چکی ہے۔ وہ ہماری اختیار کردہ ترتیب کی پابند بھی نہیں۔
بھٹو صاحب کا مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا گیاتھا۔ ہر روز بھٹوصاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے سماعت کے لیے لایا جاتا تھا۔ مرڈر ٹرائل کے نامور ترین وکلا نے ان کے کیس کی پیروی کی۔ سپریم کورٹ میں اپیل اور نظر ثانی کی سماعت بھی کھلی عدالت کے طور پر ہوئی۔ ساری دنیا نے سماعت کا منظر دیکھا۔ ٹرائل کے دوران ایک ایک گواہ پر کئی کئی روز جرح جاری رہتی تھی۔ سپریم کورٹ میں عدالت نے بھٹو صاحب کے وکلا کے ہوتے ہوئے بھی بھٹو صاحب کو خود طلب کر کے بحث کرنے کا موقع دیا۔ بھٹو صاحب نے یہ موقع استعمال کیا۔ پھر عدالت پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ فیصلہ قانونی جرائد میں چھپا ہو اہے۔ سماعت کے دنوں میں روزانہ کی کارروائی لفظ بلفظ چھپتی تھی۔ بھٹو صاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے عدالت عالیہ میں پیشی کے لیے لانے اور سماعت کے بعد واپس جیل لے جانے کی تمام کارروائی رواں تبصرے کی طرح اخبارات کی زینت بنتی۔ کیس کا فیصلہ ہوا تو فیصلے کے متن کے اردو ترجمے بھی شائع ہوئے۔ اب ریفرنس کی کارروائی شروع ہوئی ہے تو لوگ لمحہ بہ لمحہ ٹی وی چینلز کے ذریعے با خبر ہو رہے ہیں۔
راولپنڈی سازش کیس کی صورت دوسری تھی۔ اس کی سماعت خصوصی عدالت نے کی تھی۔ جملہ سماعت بھی بند کمرے میں جیل کے اندر ہوئی۔ رپورٹنگ کی اجازت نہیں تھی۔ سماعت کے لیے خصوصی قانون بنایا گیا۔ کیس کے بارے میں جملہ معلومات کو مملکت کا راز قرار دیا گیا۔ کیس کی ایف آئی آر، سماعت کی کارروائی اور فیصلہ، سب کچھ خفیہ ہے۔ کسی کو اس کی آج تک بھنک نہیں پڑنے دی گئی۔ ملزمان نے کیس کی پیروی کے لیے سید حسین شہید سہروردی کو وکیل رکھا۔ سہروردی نے کیس میں گواہ کے طور پیش ہونے والے فوجی افسران پر فن جرح کے جوہر دکھائے تو مسلح افواج کے سربراہ ایوب خان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ایوب خان کی ’’فرینڈز، ناٹ ماسٹرز‘‘ ملاحظہ فرما لیں، لگتا ہے کہ کتاب لکھواتے ہوئے بھی پسینہ خشک نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے، قبر میں بھی یہ پسینہ خشک نہ ہوا ہو۔
جناب زرداری نے موجودہ سال کو فیض کا سال قرار دیاہے۔ اس حوالے سے اس کیس کا ریفرنس بھی دائر ہو جائے تو نہایت بر موقع ہوگا۔ تاریخ کی درستی کا اطلاق صرف عدالتی فیصلوں پر ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجلس قانون ساز کو بھی اپنے گھر میں جھاڑو پھیرنا چاہیے۔ پارلیمان میں سرکاری طور پر ایک قرار داد پاس ہونی چاہیے جس میں ۱۹۵۱ء کے راولپنڈی سازش کیس کی سماعت کے لیے بنائے گئے خصوصی قانون کو سیاہ قانون قرار دیا جائے۔ قرارداد میں ۱۹۵۱ء کے اس امتیازی قانون کو پاس کرنے والی دستوریہ یا مقننہ کے ارکان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ مشکل یہ ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق ۱۹۵۱ء کے راولپنڈی سازش خصوصی ٹربیونل ایکٹ پر اس وقت کی پارلیمنٹ میں جو بحثیں (debates) ہوئی تھیں، وہ مہیا نہیں۔ اگر وہ بحثیں فراہم ہو جائیں تو مولانا شبیر احمد عثمانی، ڈاکٹر عمر ملک جیسے بہت سے بڑے بڑے مقننین کے بارے میں لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ انہوں نے اس سیاہ قانون کے بارے میں کیا کچھ ارشادات فرمایا تھا۔ واقعات کی جستجو کی جائے تو معلومات میسر نہیں۔ سرکاری سطح پر کیس کی کوئی تفصیل مہیا ہی نہیں۔ جب سرکاری سطح پر تفصیل نہ ہو تو افسانے اور کہانیاں راہ پالیتی ہیں۔ مگر ان کہانیوں کو اتنا احترام بھی حاصل نہیں ہوتا جتنا جعلی ڈگری کو حاصل ہوتا ہے۔
اس کیس کے بارے میں ایک کہانی ایوب خان کی ’’فرینڈز، ناٹ ماسٹرز‘‘ میں موجود ہے۔ ایوب خان کی سوانح میں بہت سی دوسری سازشوں کی تفصیلات بھی درج ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایوب خان اس کتاب کا نام ’’سازش نامہ‘‘ رکھ لیتے تو یہ کتاب فٹ پاتھوں پر دو دو روپے میں فروخت نہ ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان سازشوں کا مرکزی کردار تو صاحب کتاب خود تھے۔ یہ کتاب اس وقت تک کی سازشوں کی مستند ترین تاریخ کا درجہ حاصل کر لیتی۔ بہر حال سچ یہی ہے اور رہے گا بھی کہ بغاوت کامیاب ہو جائے تو احسن الانقلاب اور ناکام ہو جائے تو سازش اور غداری کہلاتی ہے۔ اس کے باوجود تاریخ کا منصف کسی کو لٹکانے کاحکم دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو پس دیوار زنداں بند بھیجتا ہے۔ وہ جب اپنا کام شروع کرتا ہے تو اس وقت تک فریقین مٹی میں مل چکے ہوتے ہیں۔ ۱۹۵۱ء کی راولپنڈی سازش کے مصنف اس وقت کے گورنر سرحد جناب آئی آئی چندریگر، زیر اعظم جناب لیاقت علی خان، ایوب خان اور ان سب کے قانونی باپ جناب جسٹس محمد منیر تھے۔ سازش کا الزام جنرل اکبر خان، بریگیڈیر صدیق اور فیض احمد فیض وغیرہ پر تھا۔ یک طرفہ تاریخ کی رو سے قصور وار ثانی الذکر ہی ہوں گے۔ آئیے ہم تاریخ کی درستی کی بات کو ترک کر کے تلواروں کے سائے میں مرتب کردہ تاریخ کے صفحات الٹنے کی کوشش کریں۔
سب سے پہلے ان سازشیوں میں سے جناب فیض احمد فیض کی گرفتاری کا منظر ملاحظہ فرمائیں۔
یہ ۱۹۵۱ء کی بات ہے۔ مارچ کی ۹ تاریخ۔ صبح کے ساڑھے چھ بجے۔ پاکستان کے ممتاز شاعر اور موقر انگریزی روزنامے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر جناب فیض احمد فیض کے گھر کو پولیس نے گھیرا ہو اہے۔ پولیس والے باربار فیض صاحب کو آوازیں دے رہے ہیں۔ جناب فیض کی اہلیہ ایلیا شور سے بیدار ہوئیں۔ بالکونی سے نیچے جھانکا تو مسلح پولیس والے لان میں داخل ہو کر جمع ہو چکے تھے۔ ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ انہوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ اگلے روز صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے تھے۔ ان حالات میں فیض صاحب نے ایلیا کو پہلے سے بتا رکھا تھاکہ ان کو الیکشنز کے کافی بعد تک نظر بند کیے جانے کا اندیشہ ہے۔ اس نظر بندی کا منشا ان کو خاموش کرنا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ فیض کی اہلیہ موقعہ کی صورت حال کے بارے میں کچھ بتا سکے، سپاہیوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور مکان کے اوپر کا صحن پولیس والوں سے بھر گیا۔ وہ سب بندوقیں تانے ہوئے تھے۔
پولیس کے موجود افسران کو فیض کے جرم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر وہ فیض کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ فیض نے پاکستان ٹائمز کے اپنے ساتھی مظہر علی خان کے مشورہ کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کردیا۔ اسی دوران مظہر علی خان گھر پر آگئے۔ ساتھ ہی پولیس نے غیر معینہ عرصے تک کی نظر بندی کا وارنٹ دکھایا۔ یہ وارنٹ بنگال ریگولیشن کے تحت جاری شدہ تھا۔ مذکورہ ریگو لیشن انگریز دور میں حکومت کے مخالفین کو قابو کرنے کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ قانون کالعدم ہو چکاتھا۔ قانون کے کالعدم ہونے کی کسی کوکیاپروا ہو گی۔منشا تو اس کو استعمال میں لاکر فوری طور پر بندے کو قابو کرنا تھا۔ مظہرخان نے یقین دلایاکہ انتخابات سے پہلے کی مختصر نظر بندی ہے، لہٰذا فیض کو پولیس کے ساتھ جانے میں کسی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں۔ اس طرح ان کو کچھ کپڑے اور بستر ہمراہ لینے کا موقع دیا گیا۔ پھر ان کو ایک جیپ کے ذریعے سرگودھا جیل لے جایا گیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کو ان کی آمد کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ فون پر رابطہ کررہاتھا کہ یکا یک وزیراعظم لیاقت علی خان نے ریڈیو پر آکریہ اعلان کیاکہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی گئی ہے۔ سازشیوں میں میجر جنرل اکبر خان چیف آف جنرل سٹاف، ان کی اہلیہ نسیم اکبر خان، کوئٹہ کے بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیرعبداللطیف خان اور فیض احمد فیض گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ لیاقت علی خان نے منصوبے کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا، البتہ یہ کہا کہ سازشی پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو طاقت کے زور پر نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب کا اچانک اعلان، عین صوبائی اسمبلی کے انتخابات (المعروف جھرلو انتخابات) سے عین ایک دن پہلے، بذات خود تمام تر سازشی اداؤں کا آئینہ دار نظر آتا ہے مگر اس کے لیے آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑے گا۔
یہ تفصیلات فیض کی گرفتاری اور بعد میں وزیراعظم کے اعلان کی ہیں۔
سوال یہ ہے کہ ایک سویلین، جس نے شاید کبھی غلیل بھی نہ چلائی ہو، وہ فوج میں تعلقات عامہ کے افسر رہے۔ اب مکمل سویلین تھے۔ انہیں فوجی جرنیلوں کے ساتھ نتھی کر کے شریک سازش ظاہرکرنا کس طرح قابل یقین ہو گا۔ چلیے شواہد کا معاملہ ہے، مگر انہیں گرفتارکرنے کے لیے جوطریقہ اختیار کیاگیا، کیا کسی مہذب حکومت کا طرز عمل اسی طرح کا ہو سکتا ہے؟ چار سال ہی پہلے، طویل جد و جہد کے بعد، ہم نے آزادی حاصل کی تھی تو ہماری قومی حکومت، قائد اعظم کے خلیفہ اول کی یہ روش،ان کے شایانِ شان تھی؟ گرفتاری کے لیے صبح سویرے کا وقت، پھر مسلح پولیس کی بھاری نفری کا اس طرح فیض کے گھر پر ریڈ ایسے ہی تھا جیسے کسی دشمن ملک پر حملہ کرنا مقصود ہو۔ فوجیں دشمن پر حملہ کے لیے، بالعموم سورج نکلنے سے پہلے کا وقت منتخب کرتی ہیں۔ یہاں ایسے ہی کیا گیا۔ چادر اورچار دیواری کے حقوق کے تصور کا اجتہاد تو ضیاء الحق کے دور میں اتحادی فقہ (PNA's jurisprudence) کا وضع کردہ تھا، لہٰذا ان کا کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا۔ کیا گرفتاری کے لیے اچانک اور اتنی بڑی مسلح نفری کی مدد سے کارروائی کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ مبینہ سازش کو بروئے کار لانے کے لیے کسی بھی ملزم نے ابھی تک کوئی عملی اقدام شروع بھی نہیں کیا تھا۔ اگرکوئی سازش تھی بھی تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتی تھی، لیکن سازش کو ناکام بنانے کے لیے ریاستی کارروائی، جس کا براہ راست وزیر اعظم نے حکم دیا تھا، ضرورت سے کہیں زیادہ افرا تفری سے کی گئی۔ اگرچہ افسر شاہی ہمیشہ ہی افرا تفری کا شکار رہتی ہے۔ سکون سے، سوچ سمجھ کر، صورت حال میں ضرورت کے مطابق مناسب ضابطے اور اخلاق کی حدود میں رہ کر، کارروائی کرنا افسر شاہی اور مقتدر لوگوں کا مزاج نہیں۔ مقتدر لوگ ہمیشہ سے خوداعتمادی کے فقدان بلکہ بحران کا شکاررہتے ہیں۔ پنڈی سازش کیس میں کارروائی کے بارے میں، وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب خود ریڈیو پر آ کر اعلان فرمائیں۔ مقصود یہ تاثر دینا تھاکہ جیسے مملکت کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے کو تھا۔ سازش کے محرکات اور وجوہات ہم الگ سے زیربحث لائیں گے۔ سرکاری اقدام اور اس کی انجام دہی کے لیے اختیار کردہ طریقہ کار کو ریاستی دہشت گردی سے مختلف کیسے تعبیرکیا جا سکتا ہے۔
آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کو کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس گرفتاری کے قریباً ڈیڑھ ماہ بعد، خصوصی عدالت کے قیام کا قانون منظور کیا گیا۔ یہ قانون صرف اس کیس کی سماعت کے لیے مر تب کیا گیا۔ اس طرح یہ ہر لحاظ سے امتیازی قانون تھا۔ ایک اچھی حکومت اس طرح کے قانون نہیں بناتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی مقننہ کے جملہ ارکان اس امتیازی قانون پاس کرنے کی پاداش میں کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لائق ہیں، لیکن جو کچھ کل تک ناروا تھا، اب روا ہو چکا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اقتدار کی حکمتیں اور مصلحتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ہم اس خصوصی قانون کا جائزہ بعد میں لیں گے، لیاقت علی خان کا بیان ذیل میں درج ہے:
’’پاکستان کے دشمنوں کی تیار کردہ ایک سازش کا انکشاف ابھی ہوا ہے۔ اس سازش کی غرض و غایت یہ تھی کہ متعدد ذرائع سے ملک میں ہلچل پید اکی جائے اور اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کی دفاعی فوجوں کی وفا داری ختم کر دی جائے۔ حکومت کو اس سازش کا بر وقت علم ہوا۔ چنانچہ آج سازش کے سرغنہ لوگوں کو گرفتار کر لیاگیا۔ میجر جنرل اکبر خان چیف آف جنرل سٹاف، بریگیڈیر ایم اے لطیف بریگیڈ کمانڈر کوئٹہ، مسٹر فیض احمد فیض ایڈیٹر پاکستان ٹائمز اور بیگم نسیم اکبر خان اہلیہ میجر جنرل اکبر خان پرمشتمل ہیں۔ سازش میں شریک دونوں فوجی افسروں کو فوراً ملازمت سے بر طرف کر دیا گیا ہے۔ قومی تحفظ کے وجوہ کی بنا پر میرے لیے یہ بتانا نا ممکن ہے کہ جو لوگ سازش میں شریک تھے، ان کی اسکیم کی تفصیل کیا ہے۔ میں اس موقع پر صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدانخواستہ ان لوگوں کی اسکیم کامیاب ہو جاتی تو اس سے ہماری فوجی زندگی کی بنیاد پر کاری ضرب لگتی اور پاکستان کا استحکام در ہم برہم ہو جاتا۔ اگر یہ سازش ناکام ہوئی ہے تو اس کا سہرا ان لوگوں کے سر ہے جو پاکستان کی سلامتی کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ یقیناًسازش کی ناکامی پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل وفاداری کے لیے ایک خراج تحسین ہے جو چند شر انگیز غدار سازشیوں کی شرارت سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور انہوں نے پاکستان کے ان دشمنوں کی ساری ناپاک کوششوں پرپانی پھیر دیا۔ ہم سب کو ان کی چوکسی کی وجہ سے خدائے تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔‘‘
’’پوری قوم اس سلسلے میں مسلح افواج کی شکر گذار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح خراج تحسین پیش کرنے میں پوری قوم میری ہم نوا ہے۔ ان افراد کو ریگولیشن ۸۰ کی دفعہ ۳ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہی کرنل محمد راجا، کیپٹن نیاز محمدارباب، میجر ضیاء الدین،میجر حسن خان، گروپ کیپٹن ظفراللہ خان پوشنی، لیفٹیننٹ خضر حیات، کیپٹن محمد اسحاق، لیفٹیننٹ کرنل نذیر احمد، محمد خان جنجوعہ، سجاد ظہیر، میجر خواجہ محمد شریف، محمد حسن عطا اور خواجہ محمد یوسف کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔‘‘ (واقعات پاکستان جلد اول صفحہ نمبر ۳۴۸، ۳۴۹، مرتبہ زاہد حسین انجم، مطبوعہ نذیر سنز پبلشرز، ۴۰ اردو بازار لاہور، سال اشاعت ۲۰۰۷ء )
اس وقت کے کمانڈر انچیف، جنرل محمد ایوب خان کی خود نوشت سے متعلقہ حصہ درج ذیل ہے:
’’میں نے کمانڈر انچیف کا منصب ۱۷ جنوری ۱۹۵۱ء کو سنبھالا۔ جنرل گریسی نے چارج دیتے ہوئے کچھ بتایا اور نہ ہی ایسے موقعوں پرایسا ممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا کہ فوج میں نوجوان ترکوں کا ایک گروہ ہے۔ اکبر خان جیسے کچھ لوگ اس میں شامل ہیں۔ دو تین ماہ بعد اکبر سازش سامنے آئی۔ یہ راولپنڈی سازش کے طور پر معروف ہوا۔ ۔ ۔ سازش کے بارے میں مجھے لیاقت علی سے علم ہوا۔ وہ انتخابی مہم پر تھے۔ انہوں نے مجھے اور اسکندر مرزا (سیکرٹری دفاع) کو سرگودھا ریلوے اسٹیشن پر ملنے کے لیے بلوایا۔ میں لاہور اور اسکندر مرزا کراچی سے پہنچے۔ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا۔ وزیر اعظم معمول کے مطابق پر سکون تھے۔ کھانے کے بعد کہنے لگے، ’’آپ کے لیے بری خبر ہے۔کچھ فوجی افسران نے حکومت الٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ اسے جلد ہی بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔ ‘‘میں نے تفصیلات پوچھیں تو انہوں نے صوبہ سرحد کے گورنر آئی آئی چندریگر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کا متن فراہم کیا۔ میں نے واقعات کی پڑتال کا مشورہ دیا۔ اسکندر اور میں گورنر سے ملنے پشاور گئے۔ ہم نے گورنر، پولیس افسر کیانی اور مخبر سے انکوائری کی۔ یہ واضح ہوا کہ طوفان آنے والا ہے۔ سازشیوں میں سے ایک بریگیڈیر صدیق خان تھے۔ وہ میرے یونٹ میں رہے۔ جذباتی اور مضطرب طرح کے شخص تھے۔ میں نے ان کو طیارے کے ذریعہ بلوایا اور ان کو بتا دیاکہ وہ سچ سچ کہہ دے، وگرنہ الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے رپورٹ کو مکمل طور پر جھٹلا دیا۔ میں نے انہیں واپس بنوں جانے کی اجازت دے دی۔ بنوں پہنچ کر انہوں نے ایک شریک سازش کرنل ارباب کو فون پر بتایا کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ حکومت الٹنے کا منصوبہ بنا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم کو اپنی انکوائری سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمیں کارروائی کی ہدایت کی۔ انسپکٹر جنرل قربان علی خان کو منظر پر لایا گیا اور تمام سازشی افسران اور سویلینز کو ان کے گھروں سے ایک ہی رات میں گرفتارکر لیا گیا۔ میرا ارادہ کورٹ مارشل کا تھا، مگر سویلینز کے ملوث ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل تھا۔ وزیر اعظم نے خصوصی ٹربیونل کے ذریعے بند کمرے کی سماعت کا فیصلہ کیا۔ حیدرآباد جیل میں مقدمہ چلا اور ملزمان نے سہروردی کو صفائی کا وکیل مقرر کیا۔ سہر وردی عجیب و غریب شخصیت تھے۔ مقدمہ میں جو فوجی افسران گواہ کے طور پر پیش ہوئے، سہروردی نے ان پر جرح میں شدید حملے کیے۔ میری نظر میں سہروردی نے حدود سے تجاوز کیا، البتہ عدالت کا رویہ مثبت ہی رہا۔ ملزمان سزاپا گئے۔ چند سال بعد،سہروردی اور ان کے ساتھی حکومت پر حاوی ہو گئے اور وہ رہا کر دیے گئے۔ سزاؤں کی معافی حکومت کا اختیارتھا۔ میں اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ فوجی افسران پر سہروردی کی جانب سے سخت، غیر ضروری اور بے وقار کرنے والی جرح کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے سہروردی کا یہ عمل ناقابل معافی تھا۔ بعد میں ہم کابینہ میں اکٹھے ہوئے، ایک موقع پر پنڈی سازش کا ذکر آیا تو میں نے سہر وردی کو گھیرا اور کہا کہ انہوں نے سماعت میں فوج کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور وہ کسی طرح بھی پاکستان کے ہمدرد نہیں۔ سہروردی خاموش رہے۔ بعد ازاں جب وہ وزیر اعظم ہوئے تو میں کراچی میں تھا۔ اسکندر مرزا نے مجھے بتایا کہ وہ سہروردی کو وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں۔ اس حیثیت میں وہ آپ کے وزیر دفاع بھی ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پرانا حساب طے کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان سے ملنے کے لیے کہا گیا۔ سہروردی ایوان صدر آئے۔ میں نے ان کو بتایا ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جواحساسات رکھتے ہیں، ان سے دونوں بخوبی واقف ہیں۔ اس کے باوجود کمانڈر انچیف کے طور وہ ہر جائز اور قانونی احکامات کی اطاعت کریں گے۔ البتہ میں یہ توقع بھی رکھتاہوں کہ وہ فوج کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ سہر وردی نے صورت حال کو قابل قبول محسوس کیا۔ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کبھی میرے معاملات میں دخل نہ دیا۔ میں جب بھی ان کے پاس گیا تو وہ ہمیشہ سننے پر آمادہ اور فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔‘‘
’’راولپنڈی سازش کی جڑیں گہری تھیں۔ اس کے بیج بے چینی اور بد اعتمادی کے ماحول میں نمو ہوئے۔ پھر مختلف اسباب نے ان کی مزید پرورش کی۔ فوج میں جونیئر افسران کو سینئرز پر ترقی دینے کی وجہ سے کافی بے اطمینانی تھی۔ اس طرح ترقی پانے والوں کی توقعات کی کوئی حد باقی نہ رہی۔ ہر کوئی یہ خیال کرنے لگا کہ جب تک وہ کمانڈر انچیف نہ بنا تو اس کا کیریئر بیکار ہی رہا۔ یہ عجیب و غریب صورت حال تھی۔ اچھے خاصے سمجھ دار لوگ، بریگیڈیئر اور جنرل رینک والے، اپنی لاٹری نکلنے کے انتظار میں رہنے لگے۔ ہر کوئی بونا پارٹ کے کردارکے لیے تیار تھا۔ میں آزادی کے بعد، بریگیڈیئر بننے پراپنے آپ کو مطمئن کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ آزادی کے بعد، میجر جنرل ہو کر اپنے آپ کو کافی سے زیادہ کامیاب خیال کرتا تھا۔ لیکن فوج میں صورت حال کافی خراب ہو چکی تھی۔۔ ۔ اس دوران کشمیر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ بے قاعدہ مہم کے طور پر شروع ہوئی۔ ہیڈ کوارٹرز سے کچھ زیادہ ڈائریکشن نہیں تھی۔ جونیئر افسر اپنے طور پر لڑائی میں مصروف و ذمہ دار تھے۔ میرے خیال میں بے اطمینانی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری حکومت اپنے فرائض مناسب طور پر ادا نہیں کر رہی تھی۔ ہم نے جب جنرل اکبر خان کے کاغذات قبضہ میں لیے تو ان میں ایک مقالہ موجود تھا۔ اس میں وزیر اعظم اور ہر دوسرے ذمہ دار شخص پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ غیر مستعد اور بر وقت فیصلے کرنے کی اہلیت سے محروم ہیں۔ اکبر خان غیر معمولی طور پر مستعد حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ بہادر افسر اور فوج میں کافی وقار کے حامل تھے۔ البتہ وہ بہت باتونی اور آرزوئیں پالنے والے شخص تھے۔وہ لوگوں کومتاثر کرنے کا فن بخوبی جانتے تھے اور اپنا ایک وسیع حلقہ اثر قائم کیے ہوئے تھے۔۔ اگرچہ مجھے کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ وہ کبھی حکومت الٹنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی مجھے ان کی کار کردگی پر کچھ شبہہ ہوتا تھا۔ میں ان کی تمناؤں، خاندانی پس منظر اور نظریاتی رجحانات کو جانتا تھا۔ مجھے اکبر خان سمیت، جب افسران کو میجر جنرل کے طور پر ترقی دینا تھی تو کچھ وقت تک اکبر خان کے بارے میں متردد رہا۔ میں نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف سٹاف کے طور پر ان کے تقرر کا فیصلہ کیا۔ میرا منشا ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا اور فوج کے کسی حصے کو براہ راست ان کے زیر کمان رکھنے سے بچنا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ چیف آف سٹاف کے طور پر اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے آزاد کشمیر میں تعینات افسران سے ملنے کو ترجیح دیتے۔ میں نے ایک دو کام ان کے سپرد کیے مگر انہوں نے وہ انجام نہ دیے۔ مثال کے طور پر میں نے ان سے کہا کہ ہمیں دشمن کے علاقے میں اپنے فوجیوں کے کیے خشک راشن جمع کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے گریز شروع کر دیا۔ یوں محسوس ہوا کہ یہ شخص یا تو غیر مستعد ہے یا اپنے کام میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ اس کا ذہن کسی اور کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ صورت حال خطرے کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اس طرح مجھے اور فوج میں صحیح سوچ رکھنے والوں کے لیے شدید دھچکامحسوس ہوا۔ فوج کا وقار سخت مجروح ہوا۔ لوگ بجا طور پر سوال کر سکتے تھے کہ پاک فوج اسی قسم کا حصار ہوتی ہے۔ فوج وفاداری، فرض شناسی، حب الوطنی اور سول اتھارٹی کے مکمل اتباع کی شاندار روایات رکھتی تھی۔ کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مملکت اتنے نازک دور میں ہو اور فوج اس طرح ابتری کا شکار ہو۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر سازش کامیاب ہو جائے تو کیاہو گا۔ میرے اندازے میں سازش کی کامیابی کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک مکمل کامیابی کی جس میں فوج کی جانب سے مزاحمت نہ ہوتی۔ اس صورت میں میرے جیسے سینئر افسران کو کسی جوابی کارروائی سے پہلے گرفتار کر لیتے۔ فوج اس تبدیلی کو قبول کر لیتی یا قبول نہ کرتی، بہر صورت اس الجھی ہوئی کیفیت میں اکبر خان اگر ہشیاری سے کام لیتے تو وہ اور ان کے ساتھی اپنے کنٹرول کو مستحکم کر لیتے۔ دوسری صورت میں اگر فوج کے کچھ لوگ مزاحمت کرتے تو فوجی یونٹوں میں تصادم ہو جاتا۔ نتیجے کے طور پر بھارتی فوج مداخلت کرتی۔ مجھے یہی خوف کھائے جا رہا تھا۔ میں اس مخمصے سے جلد ہی نکل آیا اور میں نے فوج کے وقار کو بحال کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ بیمار ذہنوں سے فوج کو پاک کیا۔‘‘ (Friends not masters pages 35-40)
ایوب خان کی کتاب سے سازش کے بارے میں درج تمام تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں۔ سازش سے نبٹنے میں وزیر اعظم اور کمانڈر چیف کے کردار کلیدی حیثیت رکھتے تھے۔ ایوب خان نے سازش کے اسباب کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ہم اس کو متنازعہ بنائے بغیر عدالتی کارروائی اور وکیل صفائی کے بارے میں ایوب کے طرز عمل پر کچھ کہنا لازم خیال کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ایک فوجی ذہن ہونے کی وجہ سے وہ صفائی کے وکیل کے حق جرح اور گواہوں کے وقار میں تصادم کے غلط تصور کا شکار ہیں۔ در اصل کورٹ مارشل میں جرح کا حق بہت محدود بلکہ برائے نام ہی ہوتا ہے، جبکہ ایک اہل اور جرات مند وکیل صفائی گواہوں کی پیش کردہ کہانی کو ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس میں کسی گواہ کے منصب اور وقار کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایوب خان وکیل صفائی کی اس حیثیت کا شعور نہیں رکھتے یا اسے مخصوص اغراض کے تحت تسلیم نہیں کرتے۔ اس بارے میں ان کی سہروردی سے کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کا لہجہ کتنا رعونت پسندانہ ہے۔ ان کے جملوں سے اس بیماری کی نشان دہی ہو جاتی ہے جو ہماری فوج میں تقسیم ہند کے بعد کینسر کی طرح پھیل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کینسر کا سرچشمہ ایوب خان کی ذات تھی۔ یہاں انہوں نے فوج کی طرف سے سول اتھارٹی کی اطاعت کی جن اعلیٰ روایات کا ذکر کیا ہے، حقیقت میں ان کا قلع قمع کرنے کا تمام تر کریڈٹ ایوب خان کو ہی جاتا ہے۔
در اصل فوجی ذہن صرف طاقت کی زبان ہی جانتا ہے۔ اس کے ذہن میں انصاف کا تصور، امریکی ڈرل مشین کے ذریعے بھی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ شروع ہی سے سول اقتدار میں فوج کی شریک ہو گئی۔ سول نظامِ incubator میں تھا،اس کے باوجود سانس بھی لینے نہ دیا گیا۔ جنرل اکبر خان اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا، اس کی حقیقی تفصیلات کہیں بھی میسر نہیں۔ حیدر آباد جیل میں بند کمرے میں مقدمہ چلایا گیا۔ خصوصی ایکٹ کے تحت قائم ٹربیونل کی جملہ کارروائی افشا کرنے کی صورت میں سرکاری راز داری کے قانون کا طلاق کر کے مقدمے کی تفصیلات پبلک تک پہنچانے سے بچایا گیا۔ اندر کیا ہوتا رہا، اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ مقدمہ کتنا منصفانہ رہا، ایوب خان کے اپنے جملے بہت واضح ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تابڑ توڑ جرح کے باوجود عدالت کا رویہ مثبت رہا۔ وہ جرح کے انداز پر برہم ہیں۔ خصوصی عدالت میں بند کمرے کی سماعت، مخصوص قانون اور ضابطے کی قید میں چلایا گیا مقدمہ، نمائشی حیثیت سے زیادہ کیا اہمیت رکھتا ہے! کاش سہر وردی کی جرح کی تفصیلات مہیا ہو جائیں تو مقدمے کی ساری حقیقت کھل جاتی۔ مقدمے میں ریکارڈ شدہ شہادت میں جعل سازی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ میں نے کہیں اس طرح کے ریمارکس پڑھے ہیں مگر حوالے ذہن سے اتر گئے ہیں۔ ایوب خان وکیل صفائی کی جانب سے سہر وردی کی جرح پر کتنے بر ہم ہیں، اس کا اندازہ اوپر ان کے اپنے جملوں سے ہو سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انصاف دینے والوں کے ذہن میں انصاف کی کون سی سطح تھی۔
راولپنڈی سازش کی مختصر سی تفصیلات زاہد حسین کی ’’واقعات پاکستان ‘‘کی پہلی جلد میں درج کی گئی ہیں۔ ملاحظہ ہو۔
’’راولپنڈی سازش کی تحقیقات کے لیے پیرزادہ عبدالستار نے ۱۳ -اپریل ۱۹۵۱ء کوقانون ساز اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جس کے تحت جسٹس سر عبد الرحمان، جسٹس چوہدری محمد شریف اور جسٹس امیرالدین احمد پر مشتمل ایک ٹربیونل کا قیام عمل میں آیا۔
فرد جرم میں قتل، شاہ برطانیہ کو سلطنت کے ایک حصے (پاکستان) سے جبراً محروم کرنے اور دوسرے حصے (بھارت) پر حملہ آور ہونے اور ملک معظم کے اغوا کی منصوبہ بندی کا ذکر کیا گیا تھا۔
۳۰۔مئی ۱۹۵۱ء کو میجر جنرل اکبر خان اور ان کی اہلیہ کو جسٹس محمد شریف کی عدالت میں پیش کیا گیا۔
۱۰۔جون لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجا اور میجر خواجہ محمد یوسف راولپنڈی سازش کیس میں سلطانی گواہ بن گئے۔
۱۸۔ جون کو اس مقدمہ میں استغاثہ کا بیان مکمل کیا گیا۔
یکم اگست کو بیگم نسیم اکبر خان کے وکیل زیڈ ایچ لاری نے سرکاری گواہ پر جرح ختم کر لی۔
۵ جنوری ۱۹۵۲ء کوراولپنڈی سازش کیس کے فیصلے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے تحت ۱۵ ملزمان میں سے گیارہ افسر اور چار شہری شامل تھے۔ بیگم نسیم اکبر خان کو بری کر دیا گیا۔ جبکہ میجر جنرل اکبر خان کو بارہ سال، گروپ کیپٹن جنجوعہ کو سات سال، میجر صادق کو سات سال، میجر ضیا الدین اور کیپٹن نیاز ارباب کو پانچ پانچ سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ لیفٹیننٹ خضر حیات، کیپٹن حسن یاخان، کیپٹن اسحاق، لیفٹیننٹ ظہیر اللہ، فیض احمد فیض، سجاد ظفر، حسن عطا کو چار چار سال قید با مشقت سنائی گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل نذیر کو تا برخواست عدالت قید کی سزا سنائی گئی۔ (واقعات پاکستان جلد اول صفحہ نمبر ۳۴۸، ۳۴۹، مرتبہ زاہد حسین انجم، مطبوعہ نذیر سنز پبلشرز ۴۰ اردو بازار لاہور، سال اشاعت ۲۰۰۷ء )
اس کیس کے حوالے سے، اس مختصر مضمون میں ہم کچھ زیادہ تبصرہ کرنے کے بجائے، وارث میر کے ایک مضمون سے کچھ اقتباسات درج کرنے پر اکتفا کریں گے۔ یہ مضمون ان کی کتاب ’’فوج کی سیاست’’ مطبوعہ جمہور پبلی کیشنز لاہور کینٹ، شائع شدہ ۲۰۰۷ء میں شامل ہے۔ اس مضمون میں وہ سازش کے ایک ملزم میجر اسحاق کے ہفت روزہ اشتراک لاہور کو ۲۱۔مئی ۱۹۷۲ء کو دیے گئے کے صفحہ نمبر ۱۱۲ تا ۱۱۴ میں لکھتے ہیں:
’’بہت سے لوگوں نے پنڈی سازش کیس کے بارے میں کئی مفروضے گھڑ لیے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کیس سے متعلق کارروائی صیغہ راز میں رکھی گئی ۔ جب پردہ ہٹے گا تو معلوم ہو گا کہ پنڈی سازش کیس کوئی سازش تھی ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں پاکستان کی حکومت پاک امریکی فوجی معاہدے کے لیے رضامند ہو چکی تھی لیکن اسے فوج میں محب وطن عناصر کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ ملک کو امریکہ کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے۔ دوسرے کشمیر میں یکم جنوری ۱۹۴۹ء کو جو جنگ بندی کی گئی، وہ پاکستان، بھارت کے حکمران طبقوں اور انگریزوں کے درمیان ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ اس کے خلاف فوج میں شدید رد عمل ہوا تھا جیسے معاہدہ تاشقند کے بعد عوام میں ہوا۔ کشمیر کی جنگ پاکستان کی طرف سے چونکہ خفیہ طور پر لڑی جا رہی تھی، اس لیے یہ رد عمل صرف ان فوجوں تک محدود رہا جو کشمیر کی جنگ میں حصہ لے رہی تھیں۔ یاد رہے کہ جن فوجی افسروں کو پنڈی سازش کیس میں ملوث کیا گیا، وہ سب کشمیر میں لڑے تھے۔ ‘‘
’’نشان امتیاز چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان کے کشمیر محاذ پر غیر معمولی جرات مندانہ کردار نے انہیں نوجوان افسروں میں بہت مقبول بنا دیا تھا۔ اسی مقبولیت نے ان میں حد سے زیادہ خود اعتمادی کی کمزوری اور خواہش انقلاب پیدا کر دی تھی۔ جنگ کشمیر میں سری نگر اڈے تک پہنچ جانے کے بعد حکومت پاکستان کے فیصلہ جنگ بندی کو اکبر خان ہضم نہ کر سکے تھے اور اسی لیے انگریز کمانڈر انچیف اور اس کے قریبی اعلیٰ فوجی افسروں کی نظر میں’مشکوک‘ تھے۔ یہ افسران صاحب مطالعہ اور صاحب تخیل تھے اور کھل کر اختلاف کا اظہار کر دینے کے بھی عادی تھے۔ جنرل گریسی نے ان کی خقیہ رپورٹ میں لکھا تھا ،’اکبر خان اپنے کیرئیر کے دوراہے پر کھڑا ہے، اسے سیاست اور فوج میں سے کسی ایک کیرئیر کا انتخاب کرنا ہو گا۔‘ میجر جنرل اکبر خان کا تقاضا تھا کہ انگریز فوجی افسروں کو انگلینڈ واپس بھیجا جائے۔‘‘ (ص ۱۱۲)
’’پنڈی سازش کیس میں ملوث جنرل نذیر محمدجنجوعہ نے اگرچہ ایک بار ریسٹ ہاؤس اٹک میں اکبر کی طرف سے دیے گئے پکنک لنچ میں شرکت کی تھی لیکن لیاقت علی خان کے سامنے اس نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا۔ یہ بات لیاقت علی خان اور ایوب خان دونوں کو سخت ناگوار‘‘ گزری تھی۔ چنانچہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں ایوب نے لکھا ہے’پاکستان کے فوجی افسر انگریزوں کو فوراً ملک سے نکال کر خود نپولین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔‘‘(ص ۱۱۳)
’’۲۳۔فروری ۱۹۵۱ء کو چیف آف دی سٹاف جنرل آفیسر میجر جنرل محمد اکبر خان کے بنگلے میں بعض فوجی افسروں کی ایک میٹنگ ہوئی جو گھنٹوں ’نقد جان پیش کروں نہ کروں‘ کے مسئلے پر غور و خوض کے بعد گو مگو کی حالت میں ختم ہوئی۔ اس قسم کے اجلاسوں کے بارے میں بعد ازاں اکبر خان کا تبصرہ یہ رہا کہ ’ہم نے وطن عزیز کے متعلق اظہارِ تشویش اور شکوہ و شکایت کے سوا، کیا ہی کیا ہے؟ہم عدالت کا سامنے کریں گے۔’ فرد جرم میں خان قربان علی خان کے قتل، شاہِ برطانیہ کو سلطنت کے ایک حصے (پاکستان) سے جبراً محروم کرنے اور دوسرے حصے (بھارت) پرحملہ آور اور ملک معظم کے اغوا کی منصوبہ بندی کا ذکر تھا۔ (سازش کیس کے ایک ملزم) کرنل حسن کے نزدیک یہ محض الزامات تھے اور گورنمنٹ پراسیکیوٹر کی فکری کاوشوں کا نتیجہ تھے۔‘‘
ایوب خان کی کتاب سے درج کردہ اقتباسات اور وارث میر کے حوالے سے ملزمان میں سے بعض کے حوالوں میں کیس کے پس منظر پر کافی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ایوب خان بھارت کی طرف سے حملے پر ہمیشہ ہی خوف زدہ رہے ہیں۔ ۱۹۶۵ء میں بھی کشمیر میں ہماری جانب سے مداخلت کے بعد ۱۹۴۹ء والی صورت حال پیدا ہوئی۔ ایوب خان کو وزارت خارجہ کی جانب سے بین الاقوامی بارڈرز کراس نہ کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ اس طرح کشمیر میں ہمارے مجاہدین اٹاری تک ایڈوانس کر چکے تھے۔ پھر بھارت نے واہگہ پار کیا تو محافظ لاہور سوئے ہوئے تھے۔ واہگہ اور چونڈہ کے محاذوں پر فوج کے اعلیٰ افسران اور جوانوں نے عظیم الشان قربانیوں سے دفاعِ وطن کاحق ادا کیا، وگرنہ ہمارے سربراہان فوج اور زعمائے مملکت تو بھارت سے دو دو ہاتھ کرنے کا تصور بھی بھول چکے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اس تصور کو پالا، ایسے میں وہ وطن دشمن، باغی اور غدار قرار نہ پائیں تو اور کیا ہوگا!
مذہبی فرقہ واریت کا سیاسی ظہور
خورشید احمد ندیم
مذہبی فرقہ واریت،ایک سونامی کی طرح،مشرقِ وسطیٰ کی سیاست کواپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔اس کی لہریں پاکستان اور افغانستان تک پہنچ سکتی ہیں۔مذہب اور سیاست کے باہمی تعلق کو نہ سمجھنے کا ایک اورخطرناک نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔
ایران کا انقلاب،9/11 کی طرح مسلم دنیا میں ایک نئے دور کا آ غاز ہے۔اس میں شا ید کو ئی مبالغہ نہ ہو کہ سیدناحسینؓابن علیؓ کی شہادت کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کی داخلی سیاست کو اتنے بڑے پیما نے پر متا ثر کیا ہے۔اس انقلاب کے بعد ہماری سیاست یقیناً وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔آج ہم مشرقِ وسطیٰ میں جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں،ان کاایک بڑا محرک یہی انقلاب ہے۔تیل کی وجہ سے اس خطے میں عالمی قوتوں کی دلچسپی نے یقیناً یہاں کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا ہے لیکن ۱۹۷۹ء کے بعد اس علاقے میں داخلی سطح پرجوتبدیلیوں پروان چڑھتی رہیں ،ان پر بہت کم توجہ دی گئی۔آج تبدیلی کا یہ عمل ایک واضح صورت اختیار کر چکا ہے، جس کے خد و خال ہم بچشمِ سر دیکھ سکتے ہیں۔
ایران کا انقلاب محض ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی،یہ شیعہ فکر میں ایک غیر معمولی تغیر بھی تھا۔روح اللہ خمینی صاحب سے پہلے شیعہ علما کا دائرہ کار مذہبی وروحانی امور میں راہنمائی تک محدود تھا۔عملاً وہ سیاسی عمل سے لا تعلق تھے۔خمینی صاحب نے ’ولایتِ فقیہہ‘‘ کا تصور دیا جس نے علما کے بھر پور سیاسی کردار کو دینی و عقلی استدلال فراہم کیا۔شیعہ علما میں ’اصولی‘ اور ’اخباری‘ دو نقطہ نظر اگر چہ پہلے ہی سے مو جود تھے اور اصولی علما اجتہاد اور روز مرہ امور میں راہنمائی کی ذمہ داری بھی ادا کر تے تھے لیکن سیاست میں ان کا کو ئی قابلِ ذکر کردار نہیں تھا۔خمینی صاحب نے ’نائبِ امام ‘ کو امام کا قائم مقام قرار دے کر اس خلا کو عملاً ختم کر دیا جو امام کی غیر مو جو دگی کے باعث پیدا ہو گیا تھا۔جب ایران میں اس تصور کوپزیرائی ملی اور ان کی قیادت میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی واقع ہو گئی تو ’اخباری ‘ نقطہ نظر عملاً ختم ہو گیااور دنیا بھر میں اہلِ تشیع نے سیاست کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔امریکا میں رہائش پزیرممتازایرانی محقق ڈاکٹر ولی نصر کے اس تجزیے سے مجھے پو را اتفاق ہے کہ اس انقلاب سے پہلے مختلف مسلمان ممالک میں اہلِ تشیع دوسری مر کزی تحریکوں کا حصہ تھے جیسے وہ مشرقِ وسطیٰ میں عرب قوم پر ستی کی تحریک،بائیں بازو کی جماعتوں اور دوسرے سیاسی فورمز سے وابستہ تھے۔اس انقلاب کے بعد وہ شیعہ تحریکوں کاحصہ بنے اور انہیں اس کے لیے ایران کی حمایت بھی حاصل رہی۔ولی نصر نے اپنی کتاب’شیعہ احیا‘ (The Shia Revival) میں بعض ایسے افراد اور ان کی سابقہ وابستگیوں کاذکرکیا ہے۔
یہ تبدیلی عملی سیاست پر کیسے اثر انداز ہو ئی، اس کا اندازہ عراق،لبنان، اردن اوربحرین کے حالات پر سرسری نظر سے ڈالنے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس مقد مے کی وضاحت میں ،میں دومثالوں کا ذکر کر تا ہوں۔۲۸۔ فروری۲۰۰۵ء کو عراق کے ایک شہر حلہ میں ایک خو ش کش حملہ ہوا جس میں ۱۲۵ شیعہ مارے گئے اور ۱۵۰ زخمی ہو ئے۔اس حملے کا ذمہ دار اردن کا ایک نو جوان منصور البنا تھا۔اس کی موت کی خبر جب اس کے آ بائی قصبے السلط پہنچی تو وہاں اسے شہید قرار دیا گیا اور تین دن تک اس کا سوگ منا یا گیا۔اس سوگ میں ان لوگوں کا کو ئی ذکر نہیں ہوا تو اس حملے میں مارے گئے۔اس پر عراق میں بہت ردِ عمل ہوا اور ۲۰ مارچ کوایک مشتعل ہجوم نے اردن کے سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔معا ملہ مزید بگڑااوردو نوں ممالک نے اپنے اپنے سفارت کار واپس بلا لیے۔عراق اور اردن کے تعلقات میں یہ تلخی پہلے نہیں تھی۔اس کا اظہار تب ہوا جب عراق میں شیعہ بر سر اقتدار آئے۔
بحرین کا معا ملہ بھی ایسا ہی ہے۔یہاں شیعہ آ بادی کی اکثریت ہے۔ایرانی انقلاب سے پہلے اخباری نقطہ نظر غالب تھا۔اس کے بعد اصولیوں کا غلبہ ہے۔اس کا سبب نقطہ نظرکی تبدیلی ہے۔یہاں ۱۹۹۴ء میں شیعہ آ بادی نے اپنے حقوق کے لیے تحریک اٹھائی۔۱۹۷۰ء میں بحرین کی آ زادی کے بعد یہ سب سے بڑا ہنگامہ تھا۔۱۹۹ء میں نئے حکمران شیخ حامدبن عیسیٰ الخلیفہ نے سیاسی اصلاحات کا اعلان کیا تو انہیں زیادہ پزیرائی نہیں ملی۔اہلِ تشیع کی طرف سے۲۰۰۲ء کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا اور اب وہاں کے شیعہ، مذہبی جماعتوں کے عَلم تلے جمع ہیں۔ان میں الوفاق اور الجبہ الاسلامیہ لالتحریر البحرین نمایاں ہیں۔۲۰۰۳ء میں جب عراق ایک بڑی تبدیلی سے گزرا تو اس کا اثر بحرین میں بھی ہوا۔ دکانوں میں خمینی صاحب اور لبنان کے شیعہ راہنماحسین فضل اللہ کی تصویرں بڑی تعداد میں آویزاں تھیں۔۲۰۰۵ء میں جب ایک مقامی اخبارنے خمینی صاحب کا ایک کارٹون شائع کیا تو بطور احتجاج ایک بڑا جلوس نکالا گیا جو ’لبیک خمینی‘ کے نعرے لگا رہا تھا۔سعودی عرب کی جو سرحد بحرین سے ملتی ہے وہاں کی آ بادی میں بھی شیعہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ سعودی عرب کو یہ پریشانی ہے کہ اگر بحرین میں شیعہ غالب آتے ہیں تو اس علاقائی قرب کی وجہ سے سعودی عرب بھی متاثر ہو سکتا ہے۔چنانچہ اس نے بحرین میں حالیہ شیعہ تحریک کو دبا نے کے لیے بحرین میں اپنی افواج بھیج دیں۔اس وقت سعودی عرب کے ان علاقوں میں شیعہ آ بادی بحرین میں فوج بھیجنے کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے۔مذہبی مسلک کے اس سیاسی استعمال کا سب سے زیادہ نقصان تصورِ قومیت کو پہنچ رہا ہے۔ اب سعودی عرب کے شیعہ شہری کی وفاداری اپنے ملک سے زیادہ ایران سے ہو تی ہے اور ایران کا سنی شہری ممکن ہے سعودی عرب یا کسی دوسرے ہم مسلک ملک سے خود کو ذہی طور پر زیادہ قریب محسوس کر تا ہو۔
مشرقِ وسطیٰ کی سیاست جس طرح مذہبی فر قہ واریت سے متاثر ہو رہی ہے،اس کے مظاہر عالمِ اسلام کے دیگر حصوں میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ عراق ایران جنگ میں ہم نے اس کی ابتدائی جھلک دیکھی۔ مجھے خدشہ ہے کہ چند دنوں تک اس کے مزید مظاہر بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ہماری مذہبی جماعتوں میں سعودی عرب اور ایران کے لیے جو نرم گوشہ ہے، اس کا اظہار ہونے لگا ہے۔ایک مسلک کے رسائل میں سعودی عرب کی حمایت کی جارہی ہے اور ان وا قعات کو سعودی عرب کی اسلامی حکومت کے خلاف ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ جواباً ایران کی حمایت میں بھی لکھا جا رہا ہے۔یہ سلسلہ جلسوں جلوسوں تک پھیل سکتا ہے۔
میرے نزدیک مذہبی فرقہ واریت کا سیاسی ظہور عالمِ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس سے امریکا جیسی قوتیں فائدہ اٹھائیں گی جن کی نظر اس خطے کے وسائل پر ہے۔ یہ مذہب اور سیاست کے تعلق کو صحیح تناظر میں نہ سمجھنے کانتیجہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی زندگی دین کے احکام کے تابع ہو نی چا ہیے اور اس سے سیاست کا کوئی استثنا نہیں ہے لیکن اہلِ مذہب نے اس کی جو تعبیر کی گئی ہے وہ محلِ نظر ہے۔ہمارے ہاں اس کا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے جماعتیں بننی چا ہیں۔ اب عملاً یہ ہوا کہ ہر مسلک کے لوگوں نے اپنی سیاسی جماعت بنالی اور انہوں نے اپنے مسلک کی روشنی میں سیاسی نظام تشکیل دینا چا ہا اور اسے اسلام کی واحد تعبیر قرار دیا۔یوں اسلامی ریاست کا تصور پاپائیت میں بدل گیا کیوں کہ اس میں مذہبی تعبیر کا حق ایک خاص گروہ کے لیے خاص ہوگیا۔اسی کانام پاپائیت ہے۔
قرار دارِ مقاصد تک حالات یہ نہیں تھے۔اس قرار داد نے ریاست کی نظری سمت کا تعین کردیا اور حکومت کا حق جمہور کو دے دیا۔اس کا منطقی نتیجہ ۱۹۷۳ء کا آئین ہے۔یہ ایک ایسی متوازن دستاویز ہے جس کے بعد مذہبی فرقہ واریت کے سیاسی ظہور کا امکان ختم ہو گیا۔اگر یہاں مذہبی سیاسی جماعتیں نہ ہوتیں تو مذہب کے نام پر کوئی سیاسی قضیہ پیدا نہ ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں سیکولرزم کا غلبہ ہوجاتا۔میرے نزدیک ایک جمہوری پاکستان کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہاں دینی مدارس ،علمی تحقیق کے مراکز اور دعوتی تحریکیں موجود ہیں،قوم کا نظری تشخص تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مذہبی سیاست کی ضروت نہیں۔یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم سے لے کر آج تک،کسی سیاسی قیادت کا مذہبی مسلک ہمارے ہاں کبھی زیرِ بحث نہیں ہوا۔اس کے بر خلاف ایران میں حکومت مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو ریاست کو آئینی طور پر ایک خاص فقہ سے منسوب کر دیا گیا۔یہی کچھ افغانستان میں ہوا جب وہاں ایک مذہبی گروہ برسراقتدار آیا۔
ریاست اور مذہب کا باہمی تعلق جس طرح پاکستان میں،آئین اور سماج کی سطح پر سامنے آیا ہے،وہ پورے عالمِ اسلام کے لیے مثال بن سکتا ہے۔اگر تمام مسلمان ملک جمہوری ہو جائیں اور قرآن و سنت کی لازمی راہنمائی پر مبنی ایک عمرانی معاہدے کو اختیارکر لیں تو مسلکی و فقہی اختلاف اجتماعیت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ عالمِ اسلام پر اپنا اثر ڈالنے کی بجائے ،ہم دوسروں کا اثر قبول کر رہے ہیں۔
(بشکریہ روزنامہ اوصاف)
شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت
مولانا محمد وارث مظہری
شیعہ سنی اختلاف بنیادی طور پر مسلمانوں کی داخلی سیاسی کش مکش کی پیداوار ہے، لیکن بعد میں اس اختلاف نے جو شکل اختیار کی، اسے اب دونوں فریقوں کی نظر میں محض فروعات دین میں اختلاف سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، تاہم اسے کفرو ایمان کا اختلاف قرار دینا بھی کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس اختلاف کو کم یا ختم کرنے کی جو سنجیدہ کوششیں ما ضی میں ہونی چاہیے تھیں، وہ بد قسمتی سے نہیں ہوسکیں۔ اب یہ اختلاف اتنی سنگین کشمکش کی شکل اختیارکرچکا ہے کہ اس کی زد میں آکر نہ جانے کتنی ہی جانیں ضائع اور نہ جانے کتنے ہی مال واسباب تباہ ہوچکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں فرقوں کے شدت پسند حلقے اس اختلاف کو کفر و اسلام کے تناظر میں دیکھنے اور پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اس طرح دونوں فرقوں کے درمیان خلیج مزید بڑھتی رہی ہے۔دونوں فرقوںیا اس کے بعض طبقات کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے انتہا پسندانہ نظریات پائے جاتے ہیں۔شیعہ کی کتابوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی ظاہرہوں گے تو و ہ سنیوں کو قتل کریں گے۔سنیوں کے یہاں یہ حدیث پیدا کرلی گئی ہے کہ: ’’اخیر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو رافضی کہلائیں گے۔اسلام کے منکر ہوں گے، لیکن اس کا لفظی اقرار کریں گے تو تم ان کوقتل کردو، اس لیے کہ وہ مشرکین ہیں‘‘۔ (یکون قوم فی آخر الزمان یسمون الرافضۃ یرفضون الاسلام و یلفظونہ فاقتلوہم فانہم مشرکون) (1) شاید اسی گھڑی روایت کی بنا پر پاکستان میں بعض انتہا پسندوں نے شیعوں کو مباح الدم قرار دے رکھا ہے۔
کسی بھی جماعت یا قوم میں دوسری جماعت کے خلاف جو ڈھلی ڈھلائی سوچ (stereotypes) بن جاتی ہے، اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فریق اپنے نظریاتی خول سے باہر آکردوسرے فریق کو خود اپنے طور پر سمجھنے اور برتنے کی کوشش نہیں کرتا۔ موجودہ دور میں دونوں فرقوں میں سے با شعور اور حساس لوگوں پرمشتمل ایک طبقہ شیعہ سنی مکالمے کوفروغ دینے کا خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں ہے، لیکن اعتراف کی بات یہ ہے کہ اس تعلق سے جتنی دلچسپی شیعہ علما اور اہل حل و عقد کے یہاں پائی جاتی ہے، اتنی دلچسپی سنی علما و اہل فکر کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ تہران میں اس کے لیے حکومت کی سر پرستی میں با ضابطہ ایک ادارہ ’’المجمع العالمی للتقریب بین المذاہب الاسلامیۃ‘‘ قائم ہے جس سے اسی مقصد کے پیش نظر ’’رسالۃ التقریب‘‘ نامی عربی جرنل شائع ہوتا ہے۔ سنی علما اور دانش وروں کی بڑی تعداد شیعہ سنت مفاہمت کے لیے اس کی طرف سے منعقد کیے جانے والے پروگراموں میں شریک ہوتی رہی ہے۔
فرقہ وارانہ مفاہمت کے لیے سب اہم طریقہ مکالمے کا طریقہ ہے۔مکالمہ متفق علیہ امور میں تعاون اور مختلف فیہ امور میں گفت و شنیدکے نکات کی تلاش کا نام ہے، اس لیے وہ ہر انسانی گروہ کی ضرورت ہے۔ چوں کہ شیعہ سنی مفاہمت مسلمانوں کے لیے اپنے داخلی حصار کو مضبوط کرنے کی ایک بہت ہی اہم کوشش ہے ،اسی لیے وہ زیادہ حساس بھی ہے۔ اس کی حساسیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں فرقوں کا یہ اختلاف صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان اختلافات کو حل کرنے سے متعلق ماضی میں گفت و شنید کی سنجیدہ کوششیں بہت کم ہو سکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے ایک بڑے اور ضروری عضو کو جسم سے کاٹ کرعلاحدہ تو کر سکتے ہیں لیکن پرسکون نہیں رہ سکتے۔یہ فطرت کے خلاف ہے۔فطرت دشمنوں کو بھی دوست بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔اسی لیے قرآن میں اس کی تاکید کی گئی ہے(2)۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ موجودہ سیاسی صورت حال میں شیعہ سنی مفاہمت بہت سے سیاسی مسائل کے حل کی کلید بن سکتی ہے۔ یہ دونوں فرقے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ان کا باہمی تعاون اجتماعی قوت و اتحاد کے ایسے دروازوں کو کھول سکتاہے جو اب تک تاریخ میں بند رہے ہیں۔
شیعہ سنی مفاہمت کے عمل کو ایک دینی وملی ضرورت کے طور پر آگے بڑھانا وقت کا تقاضا ہے جس کا مقصد تصحیح فکر و نظر کے ساتھ اسلامک اکٹو زم کوزیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز بنانا ہے۔ دونوں فرقوں کے درمیان مکالمے کے لیے سب سے پہلے اس بات پر اتفاق ضروری ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کا تعلق بنیادی عقائد اورایسے اساسات دین سے نہیں ہے جو کفر وایمان کی بنیاد ہیں۔ اس تعلق سے اہم بات جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، یہ ہے کہ شیعوں کے مختلف طبقات اورگروہ ہیں۔ان کے درمیان بہت سے بنیادی نظریات میں باہم ختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعوں کی باضابطہ الگ الگ شاخوں کے علاوہ خود اثنا عشری فرقہ مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہے۔اس لیے کوئی ایک شرعی حکم تمام شیعوں پر لگا ناانصاف کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سے ثقہ علما کا نطتہ نظر یہی ہے کہ عمومی طور پر شیعوں پرکفر کا حکم لگانے کی بجائے یہ معیار بنایا جائے کہ جو لوگ اس طرح کے عقائد رکھتے ہوں، وہ کافرہیں۔اس میں غالی شیعہ خود شامل ہو جائیں گے۔ خاص طور پر جوشیعہ قرآن میں تحریف کے شدت کے ساتھ منکر ہیں، ان کی تکفیر صحیح نہیں ہے۔
شیعہ اور سنی دونوں ہی قرآن کے اس حکم کے مخاطب ہیں کہ:’’ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو‘‘ (4)۔ قرآن کے مطابق آپسی تنازع اور اختلاف کو امت کی قوت و اثر کے ز ائل ہونے کا سبب بتایا گیا ہے۔(3) اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں امت کی جو صورت حال ہے وہ سب پر ظاہر ہے ۔ ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت نواستعماری مغربی طاقتیں شیعہ سنی اتحاد کو عملی شکل میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتیں۔ حالیہ عرصے میں غیر مسلموں: عیسائی،ہندو وغیرہ کے ساتھ مکالمے کا غلغلہ پایا جاتاہے اوراسلامی اور مغربی ملکوں میں اس پر کانفرنسیں اور سیمینارمنعقدہورہے ہیں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ خود داخلی سطح پر اس نوع کی کوشش و عمل کی ہمارے اندر شدید کمی پائی جاتی رہی ہے۔ برصغیر میں پہلے شیعہ سنی اختلاف نے اور بعد میں دیوبندی ۔بریلوی اور اہل حدیث و اہل تقلید کے اختلاف نے مسلم اجتماعیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ دیوبندی بریلوی مفاہمت پر میرے خیال میں اب تک باضابطہ طور پر صرف حلقہ دیوبند کے مشہور عالم مولانا اخلاق حسین قاسمیؒ نے قلم اٹھایا ہے۔اس موضوع پر اپنا کتابچہ انہوں نے راقم الحروف کو بھی بھجوایا تھا،لیکن کسی نے اس کوشش اور فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔اب یہ اطلاع خوش آیند ہے کہ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی دیوبندی بریلوی اختلاف وکش مکش کوختم یا کم کرنے کے تعلق سے نہایت مثبت ذہن رکھتے ہیں۔ اس وقت امت کی سب سے اہم ضرورت نظم اجتماعی کا استحکام ہے اور اس کے لیے بین مسلکی مکالمے کی ہر سطح پر ضرورت ہے ۔مکالمے کے علاوہ دوسرا انتخاب، ذاتی مطالعہ اور ذاتی غور وفکرایک یک طرفہ عمل ہے جس کا نتیجہ محدود اور وقتی ہوتاہے۔
اس مفاہمت کے عمل میں سب سے بنیادی رول شیعہ سنی دونوں فرقوں کے علما اور ارباب فکر کاہے، کیوں کہ عوام کی فکری قیادت انھی کے ہاتھوں میں ہے۔لیکن دانش وروں کے اہل فکرطبقے کے اشتراک و تعاون کے بغیر یہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے چند امور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں جن کو اس تعلق سے عمل میں لانا ضروری ہے:
حسن ظن
دو فریقوں کے درمیان نتیجہ خیز مکالمے کے لیے سب سے اہم چیز حسن ظن اور الدین النصیحۃ کے تحت خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ قرآن میں بد گمانی کی مذمت کی گئی ہے۔(5) حدیث کے مطابق بد گمانی سے بچنا چاہیے کہ بد گمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ (ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث) (6) مسلکی کش مکش میں سب سے زیادہ دخل اس بد گمانی کو ہے جو باہمی طور پر دوری بنائے رکھنے اور ایک دوسرے کوسمجھنے کی کوشش نہ کر نے کی وجہ سے عوام تو عوام، خواص کے بھی ذہنوں میں بھی راسخ ہو چکی ہے۔عوامی سطح پر ایک دوسرے کے تعلق سے نہایت بے بنیاد باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حسن ظن کے ساتھ یہ علمی اور دینی تقاضا ہے کہ اس کی حقیقت خود متعلقہ فریق کی کتابوں یا علما سے معلوم کی جائے۔ دونوں فرقوں کے تعلق سے پا ئے جانے والے اسٹیریو ٹائپس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ شیعوں کے تعلق سے بدگمانی کی ایک اہم وجہ ان کا تقیہ سے متعلق نظریہ ہے۔اس میں شک نہیں کہ اس سے متعلق جو نظریات اپنی تفصیلی شکل میں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ انتہا پسندی پر مبنی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں تقیے اور نفاق میں بظاہر کم ہی فرق رہ جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت میں بڑے پیمانے پر یہ رائج تصور کہ شیعہ سنیوں کے ساتھ ہر یا اکثر انفرادی واجتماعی امور و معاملات میں تقیہ کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔سماجی زندگی میںیہ سرے سے قابل عمل نہیں ہے۔ تاہم یہ صحیح ہے کہ غالباً تقیے کی ہی بنا پر اہل تشیع کے یہاں فکر و عمل کا تضاد پایا جاتا ہے۔
سماجی سطح پر اشتراک عمل
اس تعلق سے سب سے اہم کام یہ ہے کہ دونوں مکاتب فکر کے لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اشتراک عمل وجود میںآئے۔ اشتراک عمل سے اشتراک فکر کی بھی راہیں ہموار ہوں گی۔سنی حلقے کی طرف سے جو بھی سیاسی وسماجی پروگرام منعقدہوں، ان میں شیعہ اہل علم و فکر کی شرکت کو یقینی بنا یا جائے۔ اسی طرح شیعہ حضرات سنیوں کو اپنے اجتماعی کاموں میں شریک کریں۔ اپنے اداروں کی رکنیت دیں۔ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی مثال اس تعلق سے نمایاں ہے کہ عرصۂ دراز سے اس کے نائب صدر مشہور شیعہ عالم مولانا کلب صادق ہیں۔ مسلم پرسنل لا بور ڈ ہندوستان میں اہم اجتماعی ادارہ ہے جس کے صدور میں قاری محمد طیبؒ (سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند)، مولانا ابوالحسن علی ندویؒ ، قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ اور مولانا رابع حسنی ندوی( موجودہ) جیسے مستند اورثقہ علما کا نام آتا ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت میں بھی شیعہ علما شریک رہے ہیں۔ہندوستان میںیہ بحث سرے سے کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ شیعوں کو مسلمانوں کی ملی و اجتماعی سرگرمیوں میں شریک کیا جاسکتا ہے یا نہیں ۔ موجودہ صورت حال میں اہل فکر شیعہ علما سنی فضلا اور ارباب علم ہنر کو اپنے اداروں سے جو ڑنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ راقم الحروف کے شناسا کئی دیوبندی فضلا،دہلی کے سفینۃ الہدایہ ٹرسٹ اورجامعہ اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ میرے خیال میں یہ اہل تشیع کی طرف سے یہ ایک مثبت پہل ہے جس کے جواب میں ہمیں بھی اپنے اداروں میں شیعوں کو جگہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں اس سیاق میں ایرانی حکومت کے اس رویے کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایران میں سنیوں کو تقریباً حاشیہ پر رکھا گیا ہے۔ تہران میں تقریباً دس لاکھ سنی ہیں، لیکن سنیوں کو وہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔اس کے بر عکس مثال کے طور پر سعودی عرب میں نہ صرف ان کی مساجد ہیں بلکہ، مجھے دو اہم شیعہ علما نے بتایا کہ مدینہ میں بھی انہیں مسجد بنانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس طرح کا امتیاز شیعہ سنی مفاہمت و تقارب میں زبردست رکاوٹ ہے۔
بہر حال دونوں فرقوں کے درمیان سماجی سطح پر دوریوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ عراق میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ازدواجی رشتے کا تعلق تقریباً 30/% فی صد ہے۔ (8) ہمارے یہاں بہ مشکل ایک فی صد ہوگا۔ اہل سنت کے وسیع النظر علما کی نظر میں یہ صحیح اور جائز ہے۔ شیخ یوسف قرضاوی انھی میں سے ایک ہیں، لیکن ہمارے اکثر علما اس جواز کے قائل نظر نہیں آتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ شیعوں کے ساتھ اسے ناجائز قرار دیا جائے۔ ایک دوسرے کے پروگراموں ،شادی وغم کی تقریبات، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازکی ادائیگی،اجتماعی افطار ،اس نوع کی دوسری سرگرمیاں دونوں فرقوں کے درمیان مفاہمت کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہیں۔
اشتعال انگیز باتوں سے احتراز
دونوں فرقوں کو اشتعال انگیز باتوں سے آخری حد تک پرہیز کرنا لازمی ہے۔ ہندوستان میں لکھنؤ میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں شیعہ سنی کشیدگی میں اس بات کا بہت دخل رہا ہے کہ دونوں فریق اپنے نظریات پر سنجیدہ علمی ماحول میں غور و خوض کے بجائے انھیں عوامی سطح پرسڑکوں پر حل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ۔اشتہارات اور جلسے جلوس جذبات کو اور بھڑکاتے ہیں۔اسی روش نے پاکستان کومسلکی کش مکش کا جہنم زار بنا دیا ہے ۔اختلاف کرنے والے ہر دو فریقوں میں ایک حلقہ انتہا پسندوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ارباب حل وعقدکے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس حلقے کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کرے۔سماجی سطح پراس کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے ۔اجتماعی عہدوں سے اس کو دور رکھے ،نئی نسل کو اس سے خبر دار و ہوشیار کرے۔اسی حلقے کو اسلام دشمن اورسماج دشمن عناصر استعمال کرکے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں۔
ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اس ذہنیت سے نکلنا ضروری ہے کہ فریق مخالف جب تک اپنے فلاں مخصوص نظریات سے دست بردار نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ مکالمہ اور تعلق سازی کی کوشش نہیں کی جا سکتی۔حقیقت یہ کہ اس شرط کے ساتھکبھی کوئی مکالمہ عمل میں آہی نہیں سکتا۔
ایک دوسرے کو اصل ماخذ کی روشنی میں سمجھنے کی کو شش
شیعہ سنی مفاہمت کے لیے ایک دوسرے کو اس کے اصل ماخذ سے سمجھنا ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔دونوں فریقوں کے پاس اختلافی لٹریچر کا تقریبا ہزار سال سے زیادہ عرصے پرمشتمل ذخیرہ موجود ہے۔ جس میں دونوں فریقوں کے یہاں بڑی مقدار میں رطب ویابس جمع ہوگئی ہیں ۔ان سے دامن بچاتے ہوئے بنیادی ماخذ تک رسائی اور اس کی روشنی میں اپنے اختلافات کا تجزیہ ایک دشوار گذارعمل ضرور ہے لیکن ناگزیر ہے۔اصل مسئلہ علمی حلقوں کی سہل پسندی اوراخلاص کی کمی کا ہے۔جو علما ذوق علم سے بہرہ ور ہیں وہ خاموش اور ان معاملات سے کنارہ کش ہیں اور کم علم و نام نہاد علما و اہل دانش اختلاف کی خلیج کے مزید وسیع کرنے کو علم کی معراج اورافتراق امت کے کام کوعبادت سمجھ کر اس میں جوش اور خشوع و خضوع کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔
جہاں تک راقم الحروف کو علم ہے ،ازہر کے تدریس فقہ کے نصاب میں فقہ جعفری اور فقہ زیدی و اباضی بھی شامل ہے۔ علی گڑھ میں سنی تھیولوجی کے ساتھ شیعہ تھیولوجی کا قیام بھی اہم اور نہایت با معنی اقدام تھا،لیکن اس کے طرز پرہندو پاک کی دینی درس گاہوں میں کوئی پہل سامنے نہیں آئی ۔ نہ شیعہ سنیوں کے مدارس کا رخ کر سکتے ہیں اور نہ سنی شیعوں کے مدارس کا۔اب اس تعلق سے پیش رفت کی ضرورت ہے۔پاکستان کے تعلق سے یہ توقع کم ہے ،ہندوستان کی ا گرکوئی قابل ذکر دینی درس گاہ اس بارے میں پہل کرے تو بلاشبہ یہ ایک تاریخی اور دور رس اثرات کا حامل قدم ہوگا۔ فقہ جعفری کی ایک خصوصیت ( اپنی بہت سی افراط و تفریط کے ساتھ ) یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کادروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس باب میں اس میں سنی مکتب فکر کے مقابلے میں حرکیت اور لچک زیادہ ہے اور اس کے عملی مظاہرایران میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔(اگرچہ ایک خاص دائرے تک ہی، کیوں کہ بہر حال راقم الحروف کو اس بات پر ہمیشہ حیرت رہی کہ آخراجتہاد کے دروازے کے ’چوپٹ کھلے ‘ رکھے جانے کے باوجود آج تک بہت سی قبیح اور غیر اخلاقی و غیر فطری رسموں مثلاً: متعہ،رسول اللہ کی تصویر کشی جس کا ایران میں بکثرت رواج ہے، پر بھی شیعہ مجتہدین کی طرف سے پابندی کیوں عائد نہیں کی جاسکی؟) اسی طرح روایات واحادیث کے باب میں اگر شیعہ حضرات یہ اصولی لچک پیدا کرنے پر آمادہ ہوں کہ عقلی طور پر روایات کے قبول وعدم قبول کا مدار جیسا کہ سنیوں کے یہاں ہے، راوی کا معتمد وغیر معتمد ہونا،ہوناچاہیے نہ کہ محض اہل بیت سے انتساب،تو وہ سنیوں کے زیادہ محفوظ، مستند اور بڑے ذخیرہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
شیعہ سنی مفاہمت میں ایک بڑی رکاوٹ صحابۂ کرام اور بعض ازواج مطہرات کے تعلق سے شیعوں میں پائی جانے والی بد ظنی، غلط نظریات اور ان کا افسوس ناک سطح پر زبانی اظہار و اصرار ہے۔ شیعوں کے ایک طبقے نے اس کو ایک بڑے کار ثواب کے طو پرا ختیار کر کررکھا ہے۔ شیعہ مجتہدین اور حکومت کے تعاون سے قائم قمُ(ایران) کے بعض اداروں کی طرف سے نہایت افسوس ناک کتابیں اصحاب رسول و ازواج مطہرات کی معاندت میں لکھی گئی ہیں ۔مثلاً ایک کتاب ’’تین سو جعلی صحابہ‘‘ ہے جو مجمع جہانی اہل بیت ،قم سے اردو سمیت کئی زبانوں میں شائع کی گئی ہے ۔بظاہر اس کا مقصد اسی شیعوں کے مشہور عام نظریے کو تقویت دینا ہے کہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد نعوذ باللہ منافقین پر مشتمل تھی۔ جب کسی فریق کی مقدس شخصیات کواس طرح ہدف تشنیع بنا یا جانے لگے تو اس کے جذبات کا برانگیختہ ہونا لازمی ہو جاتاہے اور اس طرح سارا معاملہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ سال قبل ایک بڑے شیعہ اجتماع میں جس میں خیر سگالی کے جذبے سے سنیوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، ایک ذمہ دار شیعہ مقرر نے اپنے اس نہایت بے بنیاد اور افسوس ناک نظریے کو دہرایا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد تین چار صحابہؓ کے علاوہ باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ ہمارے ایک فاضل دیوبند دوست نے وہیں کھڑے ہو کر احتجاج کیا کہ کیایہی سننے کے لیے ہمیںیہاں بلایا گیا تھا۔ راقم الحروف کا اندازہ ہے کہ شیعوں کا ایک طبقہ شیعہ سنی مفاہمت کا حامی ہونے کے باوجود تبرا اور سبّ صحابہ کو اپنا مسلک بنائے ہوئے ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ کم از کم اس سے طبقے سے کسی قیمت پر مصالحت نہیں ہوسکتی۔
اکتوبر 2009 میں دوشنبے (تاجکستان) میں ملک کے صدر کی طرف سے امام ابو حنیفہ ؒ پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں ( جس میں راقم الحروف بھی شریک تھا) بعض اہل تشیع کی ایسی ہی کسی حرکت پر شیخ ازہر، شیخ طنطاوی ؒ نے انتہائی خفگی کے عالم میں اسی قسم کی راے کا اظہار کیا تھا۔شیعہ سنی قربت ومفاہمت میں جو چیزسب سے بڑی دیوار بن کرحائل ہے، وہ بلاشبہ یہی سب وشتم صحابہ کا مسئلہ ہے۔اس تعلق سے شیعوں کے مراجع تقلید علما اور مجتہدین،ایرانی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تحریری یا زبانی سطح پرپائے جانے والے اس مظہرپرپابندی لگائے ۔ قم میں مختلف دیواروں پر اللہم العن قاتلی فاطمۃ (فاطمہؓ کے قاتلین پر اللہ کی لعنت ہو) لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکروعمرؓ کواہل تشیع حضرت فاطمہؓ ؓکا قاتل تصور کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح اہل تشیع کے یہاں اب قرآن کے محفوظ اور غیر محرف ہونے پر تقریباً اجماع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو درجنوں روایات شیعہ کی اہم اور مستند کتابوں میں پائی جاتی تھیں، ان کے بارے میں اس پراتفاق کرلیاگیاکہ وہ سب غلط اور موضوع ہیں، اسی طرح شیعہ مجتہدین کواپنے اثر ورسوخ کو کام میں لاتے ہوئے خاص طور پر خلفاے ثلاثہ(حضرت ابوبکر و عمراور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم) اور حضرت عائشہؓ اورعمومی سطح پرتمام صحابہ کرامؓ سے متعلق عوام وخواص کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جنہیں یہ بتایا گیا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرامؓ کی اکثریت (مختلف شیعی روایات کے مطابق، تین چار صحابہؓ کے علاوہ تمام کی تمام) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئی تھی اور خلفاے ثلاثہ نعوذ باللہ غاصب و منافق تھے۔ بصورت دیگر تقریب او ر مکالمے کی کوششیں بے سو د ثابت ہوں گی۔ اسی طرح اہل سنت کے ان علما کو اور جماعتوں کو جو شیعوں خاص طور عمومی سطح پر تمام اثناعشریوں کی تکفیر کرتے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے۔ اس نظریاتی تبدیلی کے بغیرشیعہ سنی اتحاد مشکل نظر آتاہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں ایک سلفی اسکالر اور مناظر کی طرف سے، جو پیس ٹی وی کے ذریعہ اہم خدمات انجام دے رہے ہیں، یزید کی شخصیت کو اہمیت دینے کے حوالے سے جو تنازع پیدا ہوا وہ سراسر مسلکی امن و آشتی کی فضا کو غارت کر دینے والا ہے۔ اہل سنت کی طرف سے ایسے لاحاصل موضوعات پر زبان کھولنے یا قلم اٹھانے سے احتراز کیا جانا ہی عین اسلامی مصلحت ہے۔
بہرحال شیعہ سنی مفاہمت وقت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ہمیںآگے بڑھ کر ایسی کوششوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ مشہور سنی داعی اسلام شیخ احمد دیدات مرحوم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ :کیا 90%فی صد سنی 10%فی صدشیعوں سے خوف زدہ ہیں کہ وہ ان سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟(9)میرے خیال میںیہ سوال اہم ہے۔اہل سنت ہر طرح سے اہل تشیع پر اثر اندازہونے کی قوت رکھتے ہیں،لیکن اس کے باوجودان کے یہاں اس تعلق سے غیر ضروری حساسیت اور بے جا تحفظ کی نفسیات پائی جاتی ہے۔
2008 میں لکھنؤمیں شیعہ وسنی حضرات نے ایک ساتھ مل کر نمازعید ادا کی۔یہ ایک نہایت خوش آیند واقعہ تھا جسے دونوں فرقوں کی دو باوقار شخصیات مولاناکلب صادق اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی کا کارنامہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ کہ صرف رسول اللہ کی اس حدیث کو بھی قابل ذکر انداز میں عمل میں لایا جانے لگے توصورت حال میں نمایا ں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے کہ ’’: ہر نیک و بد کے پیچھے اور ہر نیک و بد پر نماز پڑھو اور ہر نیک وبد کے ساتھ جہاد کرو‘‘ (صلوا خلف کل بر و فاجرو صلوا علی کل بر وفاجر وجاھدو ا مع کل بر و فاجر) (8)
بہر حال شیعہ سنی اتحاد اور مفاہمت وقت کا ایک اہم تقاضا ہے ۔ضرورت ہے کہ علما اور اہل فکر اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن میں پوری غیر جانب داری کے ساتھ سمجھتاہوں کہ مفاہمت کے تعلق سے بنیادی طور پر شیعوں کو ہی اپنے بہت سے روایتی نظریات اور طرز عمل پرنظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر مفاہمت کا خواب پورا نہیں ہوسکتا۔
مکالمے اور مفاہمت کی کوششوں کے لیے ہندوستان کی سر زمین خاص طورپر نہایت سازگار ہے۔شرط یہ ہے کہ اس رخ پر مناسب انداز میں قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔
حواشی
(1) مسائل الجاہلیۃ التی خالف فیھا رسول اللہﷺ اہل الجاہلیۃ ص:67 -المکتبۃ السلفیۃ ومکتبتہا ،قاہرہ 1397-سرورق کی عبارت ہے: الف اصلہا الامام شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب وتوسع فیہا علی ہذ الوضع علامۃ العراق السید محمود شکری آلوسی۔غالب گمان یہی ہے کہ یہ اضافہ ثانی الذکر کی طرف سے کیا گیا ہوگا)۔
(1) فصلت: 34
(2) آل عمران: 103
(3) الانفال: 46
(4) الحجرات: 12
(5) متفق علیہ
(http://soundvision.com/info/muslims/shiasunni.asp (6
(http://www.islamawareness.net/Deviant/Shia/iran.html (7
(8) بیہقی و دارقطنی عن ابی ہریرہؓ
قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
مذکورہ بالا عنوان پر مولانا محمد یونس قاسمی، حافظ عبد المنان معاویہ اور راقم الحروف کی گزارشات ’الشریعہ‘ کے مارچ اور اپریل کے شماروں میں قارئین کی نظر سے گزر چکی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ دونوں طرف سے ضروری باتیں سامنے آچکی ہیں اور اب کسی مزید بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی، مگر مولانا محمد یونس قاسمی نے اپنے تازہ مضمون میں ایک دو باتیں ایسی فرمائی ہیں جن کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے۔
انھوں نے راقم الحروف کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی کسی منسوخ آیت سے استدلال کیا ہے۔ حیرت کے ساتھ یہ بات پڑھنے کے بعد میں نے اس سلسلے کے اپنے مضامین پر پھر ایک نظر ڈالی ہے، اس لیے کہ میں نے تو اپنے مضامین میں قرآن کریم کی صرف ایک ہی آیت کریمہ کا حوالہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ’’وماہم بمومنین‘‘، وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور آیت کریمہ کا حوالہ میرے مضامین میں استدلال کے طور پر موجود نہیں ہے اور اس آیت کے منسوخ ہو جانے کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر اس کے منسوخ ہو جانے پر کوئی حوالہ موجود ہو تو میں اس سے باخبر ہونا چاہوں گا، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ قرآن کریم کے اس جملے میں ان منافقین کے مومن نہ ہونے کی ’خبر‘‘ دی گئی ہے جبکہ نسخ صرف احکام میں ہوتا ہے۔ ایمانیات اور اخبار نسخ کے دائرے کے امور نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے قرآن کریم کے حوالے سے ’’مسجد ضرار‘‘ کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے نسخ کی کوئی صورت بھی کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے استدلال کی بنیاد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طرز عمل اور معاشرتی رویے پر رکھی ہے کہ ان منافقین کے مومن نہ ہونے کے باوجود معاشرتی معاملات میں یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل شریک رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں نہ صرف معاشرتی امور بلکہ مذہبی معاملات میں بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے میں ہی مصلحت سمجھی ہے اور یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آخر تک رہا ہے۔ ’اخرج فانک منافق‘ قسم کا کوئی واقعہ اگر ہوا بھی ہے تو وہ شخصی واقعہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی رویے اور پالیسی کا آئینہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ طرز استدلال اہل حدیث حضرات کا ہے کہ کسی جزوی واقعہ یا ایک آدھ روایت کو بنیاد بنا کر پورے موقف کی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ احناف کا طرز استدلال اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے ہاں مجموعی صورت حال کو سامنے رکھا جاتا ہے، صحابہ کرام کے اجماعی تعامل کو دیکھا جاتا ہے اور تمام متعلقہ روایات جو میسر ہوں، ان کا جائزہ لے کر موقف طے کیا جاتا ہے۔
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان منافقین کے بارے میں یہ تھاکہ چند معر وف منافقین کے علاوہ صحابہ کرام کی صفوں میں موجود ان منافقین کی نشان دہی تک نہیں کی گئی۔ انھیں الگ کرنے اور معاشرتی طور پر انھیں علیحدہ قرار دینا تو بعدکی بات ہے۔ اس سے قبل ان کی جو نشان دہی ضروری قرار پاتی ہے، اس کا مرحلہ بھی نہیں آیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چودہ منافقین کے نام بتائے اور وہ بھی صرف حضرت حذیفہ بن الیمان کو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان میں سے کسی کا نام اور کسی کو نہیں بتائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے انھیں کئی بار کرید کر پوچھنا چاہا مگرحضرت حذیفہؓ نے امیر المومنین حضرت عمرؓ کو بھی ان میں سے کسی منافق کا نام بتانے سے انکار کر دیا جس پر حضرت عمرؓ نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ کسی عام شخص کے جنازے پر اگر حضرت حذیفہؓ موجود ہوتے تو حضرت عمرؓ جنازہ پڑھتے تھے، ورنہ یہ سوچ کر جنازہ پڑھنے سے گریز کرتے تھے کہ یہ میت کہیں ان چودہ منافقین میں سے کسی کی نہ ہو۔ جہاں منافقین کے ناموں تک کو خفیہ رکھنے کا اس قدر اہتمام موجود تھا، وہاں معاشرتی طور پر انھیں الگ کر دینے اور ان کا بائیکاٹ کر دینے کی بات عملی طور پر کس طرح ممکن ہے؟
مولانا محمد یونس قاسمی کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ منافقین کے معاشرتی بائیکاٹ کی بات خود قرآن کریم نے ایک جگہ کی ہے جس کا ذکر سورۃ الفتح کی آیت ۱۵ میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو منافقین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے، ان سے کہا گیا کہ اگلی جنگ میں تم مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکو گے، چنانچہ غزوۂ خیبر میں وہ لوگ خواہش کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، لیکن یہ مقاطعہ وقتی اور عارضی تھا، اس لیے کہ سورۃ الفتح کی اس سے اگلی آیت ۱۶ میں ان منافقین سے کہا گیا ہے کہ:
’’تمھیں عنقریب ایک اور قوم کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی جائے گی جو بڑی سخت پکڑ والی قوم ہے۔ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمھیں اچھا اجر عطا کریں گے اور اگر تم پھر گئے جیسے تم اس سے پہلے پھر جاتے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمھیں سخت عذاب سے دوچار کر دے گا۔‘‘
مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ یہ سخت پکڑ والی قوم (اولی باس شدید) جس کے مقابلے کے لیے منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کی قرآن کریم خود دعوت دے رہا ہے، مسیلمہ کذاب کی قوم تھی اور وہ قبیلے تھے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ کہنا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں منافقین کو مسجدوں سے نکال دیا تھا اور انھیں اپنی صفوں سے الگ کر دیا تھا، ایک خواہش تو ہو سکتی ہے مگر امر واقعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جب منافقین نے اپنی الگ مسجد بنا کر جداگانہ تشخص قائم کرنا چاہا تو قرآن کریم نے اسے ’’مسجد ضرار‘‘ قرار دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے سے منع کر دیا تھا اورجناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ’’مسجد ضرار‘‘ کو گرا کر بلکہ نذر آتش کر کے ان کے علیحدہ تشخص کے امکان کو ہی ختم کر دیا تھا۔
میری طالب علمانہ رائے کے مطابق وہ منافقین جنھیں قرآن کریم نے صراحتاً ’وما ہم بمومنین‘ قرار دیا ہے اور وہ متذبذب اعرابی مسلمان جن کا قرآن کریم نے ’لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا‘ کے عنوان سے ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی پالیسی یہ رہی ہے کہ انھیں الگ تشخص قائم نہ کرنے دیا جائے، بلکہ انھیں اپنے ساتھ رکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرگرمیوں پر پوری نظر رکھتے ہوئے ان کے شر سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکیمانہ پالیسی کا نتیجہ تھا کہ وہ منافقین جن کی تعداد غزوۂ احد کے موقع پر ایک ہزار میں سے تین سو بتائی جاتی ہے، اپنا الگ تشخص اور مورچہ قائم نہ کر سکنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلم سوسائٹی میں تحلیل ہوتے چلے گئے اور جنگ یمامہ اور مرتدین کے خلاف جہاد کے بعد ان کا کوئی اکا دکا نشان بھی تاریخ کے تذکرے میں موجود نہیں ملتا۔
مولانا محمد یونس قاسمی نے ایک بار پھر فتووں کی بات چھیڑی ہے، جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاملہ فتاویٰ کے دائرے کا نہیں بلکہ معاشرتی اور قومی ضروریات کے دائرے کا ہے۔ انھوں نے دار العلوم دیوبند کے فتویٰ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمیں اس فتوے سے پوری طرح اتفاق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خاندانی شرعی قوانین کے تحفظ کے لیے ’’آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ‘‘ کے عنوان سے جو مشترکہ فورم کام کر رہا ہے اور اہل تشیع بھی اس کا حصہ ہیں، کیا دار العلوم دیوبند اس سے الگ تھلگ ہے؟ ا س بورڈ کی تو بنیاد ہی حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قدس اللہ سرہ العزیز کی صدارت میں رکھی گئی تھی اور وہ تاحیات اس کے صدر رہے ہیں۔ اور کیا حرمین شریفین میں اہل تشیع کو مسلمانوں کے ساتھ نمازوں، روزوں، حج، تراویح اور دیگر عبادات میں شریک ہونے سے روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے؟ جن چند بزرگوں نے مقاطعہ کی بات کی ہے، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن آج بھی علماء امت کا اجماعی تعامل کیا ہے؟ اور ہمارے مراکز کی عملی پالیسی کیا ہے؟ اگر ہم شخصی آرا اور اجماعی تعامل میں فرق محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر معروضی حقائق اور ملی ضروریات کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکیں تو اکابر کے عملی فیصلوں کی حکمتوں کو سمجھنا آج بھی مشکل نہیں ہے۔
مکاتیب
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(۱)
محترم جناب عمار خان ناصر صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
محترم ڈاکٹر محمود احمدغازی مرحوم پر الشریعہ کا خصوصی شمارہ اوراپنی تالیف’’توہین رسالت کا مسئلہ۔چند اہم سوالات کا جائزہ‘‘ ارسال فرمانے کا شکریہ۔ثانی الذکر کے بالاستیعاب اوراول الذکر کے چنیدہ مقامات کے مطالعہ کا موقع ملا۔ ان دنوں توہین رسالت کے مسئلہ کے زیر بحث آنے کے تناظر میں راقم کی رائے ہے کہ توہینِ رسالت پر سزائے موت ہی ہونی چاہیے اور سزائے موت کا قانون نہ صرف باقی رہنا چاہیے،بلکہ اس قانون پر کسی بھی دوسرے قانون پر عمل درآمد کے سلسلہ میں متصور مستعدی سے کہیں زیادہ مستعدی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ وطنِ عزیز کے معروضی حالات اوراہلِ وطن کے احساسات کو پیش نگاہ رکھیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ لبرل اور سیکولر حضرات کا ’’فائدہ‘‘ اس قانون کے خلاف واویلا میں نہیں بلکہ اس پرموثراور بلا تاخیر عمل درآمد نہ ہونے پر واویلا کرنے میں ہے۔ معلوم نہیں یہ سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہ قانون اور اس پر موثر عمل درآمد توہینِ رسالت کے ملزموں کا ماورائے عدالت قتل روکنے کا سب سے بہتر طریق کار ہے۔اس سلسلہ میں ذرا سی کمزوری بھی، جیسا کہ گورنر سلیمان تاثیر کے قتل سے واضح ہے، ’’تمھی قاتل،تمھی مخبر،تمھی منصف ٹھہرے‘‘ ہی کا نتیجہ پیدا کرے گی۔ بلا شبہ قانونِ توہینِ رسالت اور ملزمِ توہینِ ِ رسالت کے اقدامِ قتل کے بیک وقت دفاع میں کھلا تضاد ہے اور کسی بھی عقلی ومنطقی دلیل سے اسے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ (قانون کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ ملزم انصاف کے کٹہرے میں آئے، اس کا ٹرائل ہو اور پھر اس کے معاملے کا فیصلہ ہو۔ اگر متاثر افراد نے خود سے ہی معاملات فیصل کرنا ہوں تو ظاہر ہے کہ قانون کی سرے سے ضرورت ہی نہیں) لیکن کیاکیجیے کہ یہ بھی قانون کے نفاذ میں کمزوری ہی کا کیا دھرا ہے۔ (وہ لوگ سخت بر خود غلط اور معروضی حالات کے ادراک سے یکسر قاصر ہیں جو قانونِ توہینِ رسالت پر عمل درآمد کو بھی دیگر قوانین پر عمل درآمد کا سا معاملہ خیال کرتے ہیں۔) یہاں چشم بینا کو کوئی حل اس کے سوا دکھائی نہیں دیتا کہ ادھر کسی شخص پر توہینِ رسالت کا الزام لگے اور ادھر وہ عدالت کے حصار میں ہو اور پھر انتہائی نیک نیتی سے اس کا ٹرائل یوں ہو کہ ہر آنکھ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔اگر یہ نہیں تو کہانیاں ہی ہیں اور کہانیاں ہی رہیں گی۔
اور یہ سوال شاید کرنے کا نہیں کہ قانون کی کمزوری یا سست روی کا ردعمل زیر نظر معاملے ہی میں اس سرعت سے ’’تمھی قاتل، تمھی مخبر،تمھی منصف ٹھہرے‘‘ کی شکل میں سامنے آتاکیوں دکھائی دیتا ہے؟اس لیے کہ یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہاں کوئی Metaphysical involvement ہے اور اس لیے کہ خدا وندِ قدوس نے اگر ہر چیز بالحق پیدا فرمائی ہے اور دینی تناظر میں جنون ووارفتگی کا بھی کوئی مصرف ہے ،تو وہ ذات مصطفی علیہ التحےۃ والثنا اور آپؐ کی عزت و ناموس ہے۔یہاں اس کے سوا کچھ سوجھتا نہیں کہ:
عقل گو آستاں سے دور نہیں
اس کی تقدیر میں حضور نہیں
جہاں تک آپ کی تالیف کے حوالے سے کسی خالص مبسوط علمی تنقید و تبصرہ کا تعلق ہے تو اس کی سر دست فرصت ہے نہ بساط۔ اس عاجزنے مذکورہ مسئلہ پر مختلف اہل فکر کے زاویہ نظر کے مالہ وماعلیہ کے مطالعہ کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ آپ کی تالیف کچھ مزید اہم پہلو سامنے لائی ہے۔ یہ بے شبہ نہایت مدلل اورمعلومات افزا ہے۔ میں نے کچھ چیزیں ترتیب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ہنوز کوئی قابل اشاعت چیز تیار نہیں کر سکا۔ شاید کبھی ہو جائے۔ سر دست صرف اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دلِ ناداں اس مسئلہ کو Rationalize کرنے پر مطمئن نہیں ہوا۔کوئی کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ:
اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبانِ عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے
ڈاکٹر محمد شہباز منج
شعبہ اسلامیات، یونیورسٹی آف سرگودھا
drshahbazuos@hotmail.com
(۲)
برادرم عمار خان ناصر صاحب
السلام علیکم! الشریعہ مارچ کا شمارہ مطالعہ سے گزرا۔اس شمارہ میں مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان اور پروفیسر محمد مشتاق احمد صاحب کے مضامین خاص اہمیت کے حامل ہیں۔توہین رسالت کے مسئلہ پر دونوں مضامین بے حد معتدل اور متوازن محسوس ہوئے۔خاص طور پر پروفیسر مشتاق احمد صاحب کا مضمون اپنے عنوان کی وجہ سے محسوس ہوتا تھا کہ ایک رواجی ذہن کا مضمون ہوگا۔لیکن اس مضمون کے مندرجات نہ صرف سلیس زبان لیے ہوئے ہیں بلکہ فکری توازن سے بھی آراستہ ہیں۔ایک علمی اور تحقیقی مضمون کے لیے جس متوازن اور سنجیدہ زبان و بیان کا حامل ہونا ضروری ہے اس سے یہ مضمون بخوبی آراستہ محسوس ہوا۔ توہین رسالت کے مسئلہ پر معروف ایڈووکیٹ جناب اسماعیل قریشی صاحب کی ضخیم کتاب کے مطالعہ کے باوجود ایک پیاس اور کسک باقی رہ جاتی ہے۔محترم پروفیسر مشتاق احمد صاحب کے مضمون سے مجھے اپنی یہ پیاس بجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔میرے خیال میں یہ مضمون اسلام کی رحمت اور عدل پر مبنی معتدل،متوازن اور معقول دعوت اور تعلیمات کی زیادہ صحیح ترجمانی کرتا ہے۔تاہم محترم پروفیسر صاحب کے مضمون کے اقتباس ’’اسی اصول پر طے کیاگیا ہے کہ اگر ملک کا سب سے برترحکمران حد کے جرم کا ارتکاب کرے تو اسے حد کی سزا نہیں دی جاسکے گی‘‘ میں جس بے بسی اور اسلامی قانون کی خامی کا اظہار ہوتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی ضابطہ حیات ہی کی روشنی میں مختصرالفاظ میں اس کا حل بھی بتادیاجاتا۔جناب انعام الرحمن کا مضمون حسب روایت غیر علمی انداز کا حامل ہی محسوس ہوا۔موصوف اگر ’’نیم طنزونیم استہزا‘‘کی غیر علمی عادت سے گریز کرتے تو شاید موصوف کا یہ مضمون کسی درجے میں علمی کہلانے کا حقدار کہلاتااور قارئین کے لیے دلچسپی کا سامان پیدا کرسکتا۔لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید موصوف علم اور تحقیق کے جذبے سے نہیں لکھتے بلکہ اپنی ’’طنز اور استہزا‘‘ کی عادت کی تسکین کے لیے لکھتے ہیں۔ہمارا عاجزانہ مشورہ ہے کہ جتنی جلد ہوسکے، وہ اپنی اس عادت سے جان چھڑا لیں، ورنہ شاید یہ عادت ان کی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کو گھن کی طرح چاٹ جائے ۔
’’قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت‘‘ کے عنوان کے تحت آپ کے والدمحترم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے جن خیالات کا اظہار فرمایا، اس میں بعض نکات کو ہضم کرنا خاصا مشکل محسوس ہوا۔ ان کے ارشادات کا معروضی خلاصہ یہ ہے کہ اہل تشیع کی تکفیر بالاجماع ہوچکی، لہٰذا اہل تشیع کو کافر سمجھنے کے باوجود ملت اسلامیہ کے اجتماعی مفاد اور کاز کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ تاہم جب ہم مسلم فقہا و اہل علم کے فتاویٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو اہل تشیع کو ’’کافر‘‘ ماننے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، اور جب جمہورکے عملی طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر اہل تشیع کو مسلمانوں کا حصہ ماننا پڑتا ہے۔یہ صورتحال ایک عام آدمی کو اچھی خاصی کنفیوژن اور الجھن میں ڈال دیتی ہے۔اس الجھن میں اس وقت زبردست اضافہ ہوجاتا ہے جب مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم اپنے موقف کی حمایت کے لیے دور نبوی سے استشہاد واستدلال فرماتے ہیں۔
اس استدلال کا معروضی تجزیہ کیاجائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سرداروں اور ان کے پیروکاروں کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھااور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں ان کی شمولیت واشتراک بطور ’’کافر ملت‘‘ قبول کی تھی؟ سیرت و تاریخ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔پھر یہیں سے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی اجتماعی کازیا جدوجہد میں اہل تشیع کے اشتراک اور شمولیت سے پہلے کیا جمہورالمسلمین یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ پیش آمدہ ’’دینی و مذہبی جدوجہد‘‘ میں اہل تشیع کی شمولیت بطور ایک معاون’’کافر ملت‘‘ یا ’’غیر مسلم ‘‘ اقلیت کے طور پر قبول کی جارہی ہے۔اس سوال کا جواب بھی حالات و واقعات اور تاریخ سے یقیناًنفی ہی میں ملتا ہے۔سیرت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور جمہور امت کے اس تعامل کو دیکھا جائے تواہل تشیع کی تکفیر پر مبنی مفتیان عظام اور اہل علم کے فتاویٰ پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوجاتا ہے۔ پھر اہل تشیع میں چندخاص لوگوں کے کھلم کھلا اظہار کفراور باطل عقائد کی دعوت کی پاداش میں عام لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دینے کی سزا کیوں دی جائے؟ بزرگوار محترم جناب راشدی صاحب کے موقف سے جہاں الجھن اور تناؤ میں اضافہ ہوا ،وہاں ان کے اقتباسات پر غور کرنے سے مسئلہ کا حل بھی مل گیا۔
میری عاجزانہ اور عامیانہ بساط اس الجھن کا یہ حل تجویز کرتی ہے کہ جناب زاہد الراشدی صاحب کے اقتباسات کی روشنی میں ہم اس معروضی نتیجہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی اکثریت کا معاملہ دوررسالت کے منافقین سے ملتا جلتا ہے۔جیسا کہ گروہ منافقین کونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ’’کافر ملت‘‘ ڈکلیئر نہیں کیاتھا، بالکل اسی طرح اہل تشیع کو بھی ’’ملت کافر‘‘ ڈکلیئر کرناخلاف سنت وحکمت ہے۔چونکہ منافقین کی اکثریت ’’وماہم بمومنین‘‘ کے قرآنی خطاب کے باوجود قانونی سطح پر قرآن انہیں ’’ملت کافر‘‘ قرار نہیں دیتا۔ بلکہ مسلم امت کا حصہ مانتے ہوئے انہیں خطاب کرتا ہے، قرآن ظاہری و باطنی اور فکری و نظری وعملی خرابیوں پر منافقین کی گرفت کرتا ہے۔انہیں اصلاح وتوبہ کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا اس قرآنی دعوت کے نتیجہ میں دوررسالت میں جن لوگوں نے اپنی اصلاح کرلی اور نظری و عملی نفاق سے توبہ کرلی توقرآن اس پرانہیں قانونی سطح پر ’’کافر‘‘ سے ’’مسلم‘‘ ہونا قرار نہیں دیتا بلکہ اس داخلی فساد کی اصلاح کوتوبہ اور تزکیہ کا نام دیتا ہے۔ پھر منافقین چونکہ اپنے فکری فساد کو چھپایا کرتے تھے اور کافرانہ نظریات سے محبت رکھنے اور خفیہ طور پر ان کا اظہار کرنے کے باوجودعام مسلمانوں کے سامنے ان سے مکر جاتے تھے اور اصل اسلام کا اظہار کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں ’’ملت کافر‘‘ declare نہیں کیاگیابلکہ ان کے ظاہری اظہار اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں امت مسلمہ کا حصہ سمجھا گیا۔ اگرچہ ان کی اصلاح و تزکیہ کے لیے قرآن حکیم نے اپنی درجنوں بلکہ سینکڑوں آیات میں زوردیا ہے۔ بالکل اسی طرح اکیسویں صدی میں جو بھی گروہ کافرانہ نظریات و عقائد کا گرویدہ ہواور خفیہ طور پر ان کا اظہار بھی کرتا ہو، مگر عام مسلمانوں میں اسلام کے متفقہ علیہ عقائد ونظریات کی پیروی کا دعویٰ کرے تو ان کے اس دعویٰ کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ملت اسلامیہ کا حصہ مانا جائے گااور اصل زور سیرت وقرآن کی پیروی میں ایسے لوگوں کی باطنی اصلاح و تزکیہ پر صرف کیاجائے گا۔
رہ گیا سوال مفتیان عظام اور اہل علم کے ان فتاویٰ کا جن میں اہل تشیع کی تکفیرکی گئی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی تعبیر یوں کی جانی چاہیے کہ ان فتاویٰ کا اطلاق کسی خاص فرقہ اورمعروف گروہ یا جماعت پر کرنے کی بجائے ملت اسلامیہ کے ہر فرقہ اور گروہ کے ان افراد پر ہوگا (چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت ہی کیوں نہ کہلواتے ہوں) جو ان فتاویٰ میں بیان کیے گئے کفریہ عقائد و نظریات کے کھلم کھلامدعی اور دعویدار ہوں۔ اور جو لوگ عام مسلمانوں کے سامنے ان باطل نظریات و عقائد کو غلط مانیں انہیں ان فتاویٰ کی گرفت سے آزاد سمجھا جائے، چاہے وہ اہل تشیع کے فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور فرقہ سے۔
مولانا زاہد الراشدی صاحب کے استدلال و استشہاد سے ہمیں اپنی اس سوچ کو پختہ کرنے کا موقع ملا ہے کہ باطل نظریات و عقائد کے ایسے پیروکارجو خود کو مسلمان کہلواتے ہوں اور عام مسلمانوں سے کفریہ عقائد کو چھپاتے ہوں اور عام مسلم عقائد کے مدعی ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کوتسلیم کرتے ہوں تو ایسی صورت میں چاہے ایسا کو ئی ایک شخص ہویا کوئی گروہ یا فرقہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ ان کی اصلاح اور تزکیہ پرپورا زور اور کوشش صرف کی جائے گی۔ہاں باطل نظریات اور کفریہ عقائدکا بطلان اور نکیرببانگ دہل کی جائے گی اور اس میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔
اس بحث میں جہاں تک اہل تشیع کی بالاجماع تکفیر کے مسئلہ کا تعلق ہے تو بزرگوارم زاہدالراشدی دامت برکاتہم نے جو معروضی حقائق بیان فرمائے ہیں اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ اہل تشیع کی تکفیر پر امت کا اجماع نہیں ہے۔ بلکہ اہل تشیع میں رائج بعض بدترین گمراہیوں اور خرابیوں کے باوجود امت کا اجتماعی ذہن انہیں بالعموم ملت اسلامیہ کا حصہ ہی سمجھتا رہا ہے اور اسی حیثیت سے ان کے تعامل واشتراک کو بھی قبول کیاجاتا رہا ہے۔تاہم اس کے باوجود ہمیں اپنے نتائج فکر پر اصرار نہیں ہے۔اوپر بیان کیے گئے معروضی حقائق سے اگرکوئی دلائل سے ہمارے نتائج فکر کا غلط ہوناثابت کردے تو ہم دل کی پوری آمادگی سے اپنی فکر کی اصلاح کرلیں گے۔اس ساری بحث میں جناب راشدی صاحب مدظلہ کا یہ موقف طالبان علم کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے کہ:
’’میرے والد محترم اور حضرت صوفی صاحب کا زندگی بھر یہ معمول رہا ہے کہ وہ بہت سے معاملات پر اپنے تحفظات کا اظہارکرتے تھے اور رائے بھی دیتے تھے، لیکن جب کوئی اجتماعی فیصلہ ہوجاتا تھا تو اسے نہ صرف قبول کرلیتے تھے بلکہ اس کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔خود میرا معمول بھی بحمداللہ تعالیٰ یہی ہے کہ بعض معاملات پر اپنی مستقل رائے رکھتا ہوں، اس کا اظہار بھی کرتا ہوں اور کوئی مناسب موقع ہوتو اس پر بحث و مباحثہ سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن عملاً وہی کرتا ہوں جو اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے اور جمہور اہل علم کا موقف ہوتا ہے، رائے کے حق سے میں کبھی دست بردار نہیں ہوا لیکن اپنی رائے کو حتمی قرار دے کر جمہور اہل علم کے موقف کے سامنے اڑنے سے ہمیشہ گریز کیا ہے اور اسے کبھی حق اور صواب کا راستہ نہیں سمجھا۔‘‘
محمد رشید
مکان نمبر336/50،گلی نمبر3
شاہ فیصل کالونی رجوانہ روڈ، ملتان
(۳)
محترمی ومکرمی!
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ........ مزاج گرامی!
آج کی ڈاک سے الشریعہ کا ڈاکٹر محمود احمد غازی نمبر موصول ہوا جسے دیکھ کر آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی کی شخصیت اور ان کے افکار وخیالات پر ’’الشریعہ‘‘ نے خصوصی نمبر شائع کر کے اس میدان میں سبقت تو حاصل کر لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نمبر کی پیشکش (خوب صورت بائنڈنگ، عمدہ کاغذ، عمدہ طباعت اور معیاری مقالات) کی صورت میں اپنی اعلیٰ اہلیت اور مہارت کا لوہا بھی منوا لیا ہے۔
آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہمارے دینی حلقے اس بنا پر دوسروں کی تعریف اور ان کے لیے کلمات خیر کہنے سے بچتے ہیں کہ مبادا اس سے کہنے والے کا مقام فروتر شمار نہ ہو۔ اسی بنا پر دینی حلقوں میں بڑی بڑی قد آور شخصیات انتقال کر جاتی ہیں اور ان پر مقتدر دینی حلقوں کو دو لفظ کہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ برسوں پہلے شیخ سعدی فرما گئے تھے:
نام نیک رفتگاں ضائع مکن
تا بماند نیک نیکت برقرار
آپ اور آپ کے والد محترم (اللہ تعالیٰ انھیں سلامت رکھے، اللہ رب العزت نے انھیں حالات حاضرہ کو سمجھنے اور ان کا تجزیہ کرنے کا خصوصی فہم اور سلیقہ عطا کیا ہے) جو شمع جلائے بیٹھے ہیں اور جس کی روشنی سے اپنے اور بیگانے سبھی مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے دینی حلقوں میں ایک منفرد مثال ہے۔
مجھے افسوس ہے کہ میں اس بزم میں شرکت نہیں کر سکا، لیکن چونکہ ’’قافلہ ادب اسلامی‘‘ بھی اس عنوان پر خصوصی نمبر شائع کر رہا ہے، اس لیے امید ہے، اس کے ذریعہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔
اس نمبر کی اشاعت پر میری طرف سے دلی مبارک باد قبول فرمائیے۔ والد محترم مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم کی خدمت میں تسلیمات۔
ڈاکٹر محمود الحسن عارف
اردو دائرۂ معارف اسلامیہ
پنجاب یونیورسٹی، لاہور
(۴)
محترم ومکرم جناب عمار خان ناصر صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ماہنامہ الشریعہ کا خصوصی شمارہ بیاد مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب موصول ہوا۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر عرصہ میں چھ سو ضخیم صفحات پر مشتمل خصوصی اشاعت شائع کر کے عصر حاضر کے ایک عظیم محقق کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
یقیناًڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس قابل تھی کہ ان کی وفات پر ان کے حالات زندگی، ان کے علمی وفکری رجحانات اور سب سے بڑھ کر ان کی وسعت نظری پر، جس پر کسی خاص مسلک کی چھاپ نہ تھی اور خاص گروہی دائرے سے نکل کر پوری امت مسلمہ کے مسائل کو دیکھنے اور اسے حل کرنے کی صلاحیت تھی، خصوصی اشاعت کا اہتمام ہو۔ یہ سعادت الشریعہ کے حصے میں آئی ہے اور الشریعہ نے اسے خوب نبھایا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے آ گئی ہے۔
بدقسمتی سے برصغیر میں دینی ومذہبی رہنماؤں اور قیادتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے خاص گروہی دائرے سے باہر نہ نکلنا ہے جس کی وجہ سے سیکولر طبقہ ہمیشہ سے عوام کو یہ باور کروانے میں کامیاب نظر آتا ہے کہ جو مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ پاکستان میں کیا اسلام لائیں گے؟ اور اگر یہ اسلامی نظام لانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو کون سی فقہ نافذ کریں گے یا کس گروہ کے اسلام کو نافذ کیا جائے گا؟ اگرچہ علماء کرام نے مل کر اس کا جواب دے دیا تھا، مگر وہ صرف دستاویزات کی حد تک ہی محدود رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے مذہبی گروہوں کے درمیان ابھی تک فاصلے باقی ہیں اور یہ فاصلے جلد ختم ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر گروہ اپنے پاس جو کچھ ہے، اسی پر خوش ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اغیار کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کے درمیان مزید اختلافات پیدا کریں اور ان کو تقسیم در تقسیم کریں۔ گورنمنٹ کی جانب سے ناموس رسالت ایکٹ پر ترمیم کے خلاف اگرچہ تمام دینی وسیاسی جماعتوں اور دینی رہنماؤں کی یک جہتی نظر آتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اتحاد بھی جلد ختم ہوجائے گا۔ ان پریشان کن حالات میں ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کی شخصیت ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ ہم بھی ان کی طرح گروہی ومسلکی تعصبات سے بالاتر ہو کر سوچیں اور عالم کفر کی اسلام کے خلاف زہریلی مہم کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے لیے ٹھوس لائحہ عمل اپنائیں۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے پرزور جدوجہد کریں اور اسلام کو اس دور میں بھی قابل عمل بنانے کی سعی پیہم کریں۔
سعید احمد الحسینی
مرکز تعلیم وتحقیق، قرآن اکیڈمی
یاسین آباد، کراچی
(۵)
محترمی ومکرمی مولانا ابو عمار زاہد الراشدی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اپریل ۲۰۱۱ء کے شمارے میں برادرم عبد المنان معاویہ کا خط اور آنجناب کا جواب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اسی سلسلے میں کچھ جذبات وتاثرات عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے بھی فرمایا ہے کہ ’’جذبات وتاثرات کو سینے میں گھٹے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کا اظہار ہونا چاہیے اور ان پر ایک جائز حد تک کھلا مباحثہ بھی ہونا چاہیے۔‘‘
۱۔ آپ نے فرمایا کہ آپ قادیانیوں سے بھی قومی ومعاشرتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں خود قادیانی رکاوٹ ہیں۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ محقق اہل سنت، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید ؒ نے تحفہ قادیانیت ص ۵۹۱ میں فرمایا ہے کہ ’’پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، لیکن قادیانیوں سے اپنے آپ کو غیر مسلم شہری (ذمی) تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح وہ غیر مسلم ذمی نہیں، بلکہ ’’محارب کافر‘‘ ہیں اور ’’محاربین‘‘ سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔‘‘
۲۔ قادیانی اور اہل تشیع دونوں اسلام کے نام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ بھی ایسی کہ جو ملک کی صورت حال میں گڑبڑ پیدا کرتی ہے۔ قادیانی اور اہل تشیع دونوں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ پھر توقع رکھتے ہیں کہ معاشرے کا امن قائم رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل فساد کی جڑ تو یہ ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہماری تو ایمانی ودینی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کھائیں پئیں، ان کو اپنی مجالس میں شامل کریں یا ان کی مجالس میں شریک ہوں۔ آپ کی ایمانی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟
۳۔ اپ اپنے ساتھ اہل تشیع کو ملا کر خوش ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم میں اتحاد ہے تو آپ اس اتحاد کو کیا نام دیں گے؟ ’’اتحاد بین المسلمین‘‘ یا ’’اتحاد بین المسلمین والکافرین والکاذبین‘‘؟ آپ نے اپنے ساتھ اہل تشیع کو ملایا ہوا ہے اور قادیانیوں کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں، مگر اپنے مسلک کی جماعت سپاہ صحابہ کو آپ نے اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
۴۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اہل تشیع کا معاملہ حل کرنا ہے تو اس کا آغاز حرمین شریفین سے ہونا چاہیے۔ عرض ہے کہ جب قادیانیوں کا مسئلہ حل ہوا تھا تو کیا وہ حرمین شریفین سے حل ہوا تھا؟ مودبانہ عرض ہے کہ جب اپنا پیٹ بھوکا ہو تو پہلے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اس لیے تمام اکابر علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کا جلد اجتماعی فیصلہ کریں۔ محقق اہل سنت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہیدؒ نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ کے سامنے شیعوں کی کتابیں اور آڈیو کیسٹیں پیش کی تھیں۔ سید سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ’’مجھے ہٹایا اس وجہ سے گیا تھا کہ میں دلائل کے سامنے جھک گیا تھا۔ یہ فیصلہ کر رہا تھا۔‘‘ مگر یہ فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ان کو ہٹا دیا گیا، ورنہ آج شیعہ یہاں غیر مسلم ہوتا۔ ہم حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کو ری اوپن کرے تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے۔
۵۔ ہم سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں کہ اپنو ں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اپنوں میں لاکھ غلطیاں کوتاہیاں سہی، مگر مسلمان کے ساتھ مسلمان اچھا لگتا ہے۔ مسلمان کے ساتھ کافر اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ کافروں کو ساتھ بٹھائیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا اور عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اکابرین امت فرما گئے ہیں کہ اہل تشیع کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ ہم کس کی بات مانیں؟ آپ کی یا پہلے والے اکابرین امت کی؟ اگر ہم ان کی بات کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ جیسے بزرگ ہی ہمارے اوپر یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہم سپاہ صحابہ والے اکابر کے گستاخ ہیں۔ آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ کس کو اپنا دکھ درد بتائیں؟ اگر آپ جیسے بزرگ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے تو پھرہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں۔ خدارا! آپ کا جو مقام بنتا ہے، آپ اپنے اس مقام کو پہچانیں۔ جب آپ جیسے بزرگ ایسی تحریرات لکھیں گے تو پھر ہم جذبات میں نہ آئیں تو اور کیا کریں؟
۶۔ ہم مانتے ہیں کہ اکابر نے اہل تشیع کا ساتھ دیا ہے، مگر اکابر سے ہٹ کر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں اہل تشیع کیا ہیں؟ مسلمان یا کافر؟ اگر کافر ہیں تو پھر ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کو اپنی مجالس میں شامل کرنا یا ان کی مجالس میں شریک ہونا شرعاً کیسا ہے؟ ان دو سوالوں کے شرعی حوالے سے جوابات دے کر اپنا ایمانی فریضہ ادا کریں۔ خصوصاً مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جوابات قرآن وسنت کی روشنی میں دے کر امت مسلمہ کو کفریہ عقائد سے بچائیں۔
حافظ محمد حسن الحسینی
(۶)
محترمی ومکرمی محمد عمار خان ناصر صاحب
السلام علیکم
ماہنامہ الشریعہ، اپریل ۲۰۱۱ء میں جناب چودھری محمد یوسف اور شفقت رضا منہاس ایڈووکیٹ صاحبان کا مضمون ’’کورٹ میرج: چند قانونی اور معاشرتی پہلو‘‘ نظر سے گزرا۔ چار مرتبہ عرق ریزی اور جاں فشانی سے پڑھنے کے باوجود میں مضمون کی اساس تک پہنچنے سے مکمل طورپر قاصر رہا، کیونکہ حسب روایت عنوان اور مضمون میں کوئی تال میل نظر نہ آیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بقول محترم مضمون نگار صاحبان ’’وکلا ذہین لوگوں کا پیشہ ہے‘‘، جبکہ میں ذہانت کی اس معراج پر ابھی نہیں پہنچ پایا جہاں حقائق اور موز واسرار مجھ پر یوں منکشف ہوں جیسے وکلا حضرات پر ہوتے ہیں۔
دونوں حضرات بات کورٹ میرج سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر حضرات کو رگڑتے ہوئے قاری کو گھسیٹ کر عدالت کے کٹہرے میں لے جاتے ہیں۔ پھر بطور اتھارٹی ’’مارننگ ود فرح‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے آخر میں بڑے پروفیشنل انداز میں ’’میں باغی ہوں‘‘ کہہ کر اپنی جان خلاصی کروانا چاہتے ہیں۔ جناب ایڈووکیٹ صاحبان! پہلے تو قانونی تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر یہ بتایا جائے کہ کیا پاکستان میں ’’کورٹ میرج‘‘ کے عنوان سے شادیاں نہیں ہو رہیں؟ (قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے)۔ اگر ہو رہی ہیں تو پھر آپ کے دوست کی بیٹی کا thesis بھی درست ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی راہنمائی کرتے، نہ کہ اس پر اپنی رائے ٹھونستے۔ مضمون نگار صاحبان خود ہی کورٹ میرج کے تصورکی نفی کرتے ہیں، پھر خود ہی اس سلسلے میں عدالت میں پیش بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ ذہین پیشے سے وابستہ افراد کے نظریہ اور عمل میں کھلا تضاد نہیں؟
محترم مضمون نگار صاحبان رانی توپ کا رخ پروفیسر حضرات کی جانب کرتے ہوئے چند ثانیوں کے لیے یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کے مضمون کا عنوان کورٹ میرج ہے نہ کہ تعلیمی اداروں میں بورڈ آف گورنرز کے خلاف طلبہ اور اساتذہ کا رد عمل۔ ان کو یقین ہے کہ گورنمنٹ کالجز میں تعلیم، نام کی حد تک رہ گئی ہے اور پروفیسر صاحبان صرف تنخواہ وصول کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گاکہ آج بھی سفید پوش عوام الناس کے بچوں کی کثیر تعداد انھی سرکاری کالجز میں زیر تعلیم ہے اور یہی کالجز ان کے لیے تعلیم کی آخری کرن ہیں۔ یہ بات کہ پروفیسر حضرات کی ایک تعداد صرف تنخواہ وصول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، بڑی حد تک درست ہے، لیکن وہ یہ بتائیں کہ ان چند مفاد پرست لوگوں کی بدولت تمام محنتی اساتذہ کی کردار کشی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟
کیا آپ کے ’’ذہین افراد‘‘ پر مشتمل شعبے میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں؟ کیا چند وکلا پیسوں کی خاطر اپنی مخالف پارٹیوں سے نہیں مل جاتے؟ کیا چند وکلا ججز اور سائلوں کے درمیان ’’پل صراط‘‘ کا کام نہیں کرتے؟ قانون کو تو آپ نے اپنے گھر کی باندی بنا رکھا ہے۔ قانون کے رکھوالے بھی آپ اور میرٹ کے بغیر ایم بی بی ایس میں داخلہ دلوانے والے بھی آپ۔ نظریہ ضرورت کے تخلیق کار بھی آپ اور اس کے تخریب کار بھی آپ۔ گویا قانون ساز بھی آپ اور قانون شکن بھی آپ۔ سو جس طرح ان چند ذہین مگر لالچی وکلا کے کردار کی بنیاد پر پورے شعبہ وکالت کو برا نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح چند خودغرض پروفیسرز کی وجہ سے آپ کو شعبہ تدریس سے منسلک تمام اساتذہ کرام کی کردار کشی کا بھی قطعاً کوئی حق نہیں رکھتے۔
پروفیسر محمد اویس چوہدری
شعبہ انگریزی، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، گوجرانوالہ
’’موجودہ عالمی استعماری صورتِ حال اور فیض کی شاعری‘‘
پروفیسر میاں انعام الرحمن
پاکستان میں اقبالؔ کے بعد جن شعرا کوقبولیتِ عامہ ملی ہے، ان میں فیض احمد فیضؔ نے نئی نسل کو غالباً سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ فیضؔ نے دست یاب صورتِ حال میں (in the given situation) جس متانت و سنجیدگی اور مدھر و دھیمے لہجے میں ترقی پسندانہ خیالات کا شاعرانہ اظہار کیا، تمام حلقوں نے ہمیشہ اس کا اعتراف اور احترام کیا ہے۔
حکومت پاکستان نے ۲۰۱۱ کو ’فیض کا سال‘ قرار دیا ہے۔ اکادمی ادبیات نے اس سلسلے میں فیض کانفرنس منعقد کر کے فیض احمد فیضؔ کو خراجِ تحسین پیش کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کانفرنس میں پڑھے گئے مقالات فیضؔ کو خراجِ تحسین کے بجائے ’خراج‘ ادا کرنے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ خراجیات کے اس شگوفے کی تدوین و ترتیب کا ’شرف‘ یونی ورسٹی آف گجرات کے ایڈیشنل رجسٹرار شیخ عبدالرشید صاحب کو حاصل ہوا ہے اور اسے سہواً ’’موجودہ عالمی استعماری صورتِ حال اور فیض کی شاعری‘‘ کا عنوان دیا گیا ہے۔ پونے تین سو (۲۷۵) صفحات کی کتاب میں بمشکل پانچ سات صفحات ہی ایسے ہیں جو دل فریب عنوان سے تو مناسبت رکھتے ہیں۔ ہم جیسے، ادب سے واجبی سی دلچسپی رکھنے والے موسمی نقاد بھی (جنہیں بآسانی غیر موسمی قرار دیا جا سکتا ہے) یہ بات جانتے ہیں کہ کسی ادبی صنف کو اپنا آپ منوانے میں برسوں لگتے ہیں، لیکن خراجیات کا یہ شگوفہ ایک ہی کانفرنس میں کچھ اس طرح چٹکا ہے کہ کریڈٹ لینے کی خاطر چار حریف لپکے جا رہے ہیں۔ (۱) مقالہ نگار حضرات، (۲) اکادمی ادبیات، (۳)حکومت پاکستان، (۴)یونی ورسٹی آف گجرات۔ اگر فیضؔ حیات ہوتے تو شاید پانچویں حریف وہ خود ہوتے۔
مقالات کے بین السطور مقالہ نگار حضرات مصر ہیں کہ خراجیات کا شگوفہ انہی کا مرہونِ منت ہے۔ اکادمی ادبیات کا جوابی اصرار یہ ہے کہ کانفرنس کا انعقاد نہ ہوتا تو یہ شگوفہ کیونکر ظہور پذیر ہوتا؟ کچھ اسی قسم کا دعویٰ حکومت پاکستان کا ہے کہ ۲۰۱۱ کو فیض کا سال قرار نہ دیا جاتا تو اکادمی ادبیات کو فیض کانفرنس کا خیال تک نہ سوجھتا۔ ان تینوں کی چپقلش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یونی ورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین نے خراجیات کے شگوفے کو اپنی یونی ورسٹی کے احاطے سے اٹھکیلیاں کرتے تاڑ لیا ہے۔ موصوف اسے رجھانے بلکہ ورغلانے کی کوشش میں ہیں، دیکھیے ذرا:
’’فیض احمد فیضؔ کے صد سالہ یومِ ولادت اور سالِ فیض کی مناسبت سے یہ پاکستان کی ڈیڑھ سو کے لگ بھگ جامعات میں سے پہلی یونی ورسٹی ہے جس نے انہیں یاد کرتے ہوئے کتابی صورت میں خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔ ’فیضیات‘ کے حوالے سے یہ کتاب پیش کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے مجھے طمانیت و فخر کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب فیضیات کے ضمن میں اہم حوالہ ثابت ہوگی۔‘‘ (ص ۱۱)
ڈاکٹر صاحب اناڑی نکلے۔ ان کے قلم کی لغزش (slip of the pen) نے ایک نئی ادبی صنف متعارف کروانے کا کریڈٹ کھو دیا ہے۔ افسوس صد افسوس! نوکِ قلم نے خراجیات کے بجائے فیضیات لکھ دیا ہے۔ اگر وائس چانسلر صاحب سے یہ غیر شعوری غلطی(slip of the mind) نہ ہوتی تو قوی امید تھی کہ خراجیات کا یہ شگوفہ گجرات یونی ورسٹی کے نام ہو جاتا اور یونی ورسٹی کے لیے بنیادی حوالے کی چیز بھی بن جاتا۔
اس انوکھے شگوفے کو اکادمی ادبیات کے کھاتے میں ہرگز نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ اس نے وہی کام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو مقالہ نگاروں کا اپنے کام سے (بزبانِ فیضؔ ) عشق ہے جس کی وجہ سے ایک نئی ادبی صنف ’خراجیات‘ ایک شگوفے کے مانند چٹک کر سامنے آ گئی۔ اس ادبی صنف کے مطالعے سے پہلے ہمارا گمان تھا کہ ترقی پسندی اور حقیقت پسندی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لیکن اکادمی ادبیات نے مقالہ نگاروں کو، استعماریت کے مفاہیم سے روشناس کرائے بغیر، موجودہ عالمی صورتِ حال کا ادراک کرائے بغیر، اور تو اور فیضیات کے ضمن میں چند اہم کتابیں پڑھوائے بغیر، اس پر مستزاد مقالہ نگاری کی مشق کا اہتمام کیے بغیر فیضؔ کانفرنس منعقد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نئی ادبی اصناف کی اختراع، محض ترقی پسندانہ حقائق سے ممکن نہیں، بلکہ مقالہ بازی کو فروغ دینے والے مقالہ نگاروں کے طفیل ہی اذہان میں مدفون ایسے خزانے باہر لائے جا سکتے ہیں جنہیں بعد ازاں بڑی آسانی سے خراجیات جیسا ’معتبر‘ نام دیا جا سکتا ہے۔
اب یہ شگوفہ پھوٹ نکلا ہے تو دیکھتے ہیں کہ فیض احمد فیضؔ کے بعد کس ترقی پسند کے ساتھ حقیقت پسندی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ فی الحال اس سلوک کا مستحق فیضؔ ہی ٹھہرے گا کہ حکومت پاکستان نے ۲۰۱۱ کو فیضؔ کا سال قرار دیا ہے۔ آپس کی بات ہے، اگر بھٹو کیس ری اوپن کرنے سے پہلے سالِ فیضؔ کی مناسبت سے پنڈی سازش کیس ری اوپن کیا جاتا تو تاریخ کی درستی، تاریخی درستی کے ہمراہ سامنے آجاتی اور تاریخ کی درستی کی ایک فضا بھی تیار ہو جاتی جس میں بھٹو کیس کی شنوائی خوب طنطنے اور غلغلے سے ہوتی۔ ہمارا وجدان بتا رہا ہے کہ حکومت نے یہ کام اشارتاً اکادمی ادبیات کے سپرد کر دیا تھا۔ اب اکادمی ’ سالِ فیض‘ کے مضمرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے پنڈی سازش کیس پر کانفرنس کا اہتمام نہیں کر سکی تو حکومت کا کیا قصور؟
البتہ فیضؔ کانفرنس میں گورنر پنجاب جناب سردار محمد لطیف خان کھوسہ کی صدارت، کسی حد تک اکادمی کی اشارہ فہمی کی دلیل ہے۔ اگر یہ کانفرنس ’پنڈی سازش کیس اور فیض احمد فیضؔ ‘ کے زیر عنوان منعقد ہوتی تو لطیف کھوسہ صاحب اپنے خطبہ صدارت میں اس عزم کے ساتھ گورنری چھوڑنے کا اعلان فرماتے کہ وہ خود اس کیس میں وکالت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ یار لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ منعقد شدہ فیضؔ کانفرنس میں جناب گورنر کے خطبہ صدارت سے جس درجے کی ’پختگی‘ ٹپک رہی ہے، اس سے یہ مفروضہ تقویت پکڑ رہا ہے کہ ان کا استعفا ان کی جیب میں موجود تھا۔ یہ تو کانفرنس کے رنگ ڈھنگ اور خراجیات جیسے شگوفے کو دیکھتے ہوئے گورنر صاحب عین وقت پر مستعفی ہونے سے تائب ہو گئے، ورنہ آج تاریخ کا دھارا مختلف ہوتااور بابر اعوان صاحب استعفیٰ دینے میں سبقت نہ لے جا سکتے۔
الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں حفظ قرآن کریم اور ترجمہ وعربی زبان کی کلاسز
ادارہ
الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں قرآن کریم حفظ کی کلاس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ قاعدہ اور ناظرہ قرآن کریم کے ساتھ ابتدائی دینی تعلیم کا سلسلہ اکادمی میں ابتدا سے ہی جاری ہے اور روزانہ صبح کے وقت محلے کے بچے اکادمی کی مسجد میں آکر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اب حفظ قرآن کریم کی باقاعدہ کلاس بھی شروع کر دی گئی ہے جس میں حفظ قرآن کریم اور ضروریات دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور ریاضی وغیرہ کی ضروری تعلیم بھی دی جائے گی تاکہ طلبہ حفظ قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد حسب استعداد مڈل یا میٹرک کا امتحان دے سکیں۔
اس سلسلے میں ۲۲؍ اپریل ۲۰۱۱ء بروز جمعۃ المبارک چار بجے شام ایک افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں علماء کرام، احباب اور اہل محلہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور الشریعہ اکادمی کے ڈائریکٹر مولانا زاہد الراشدی، مولانا حافظ محمد یوسف اور حافظ محمد رشید نے خطاب کیا، جبکہ جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے شعبہ تجوید کے صدر مدرس مولانا قاری سعید احمد نے دس بچوں کی کلاس کو پہلا سبق پڑھا کر حفظ قرآن کریم کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر قاری صاحب موصوف نے اپنے مخصوص انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ تقریب کے اختتام پر کلاس کی کامیابی اور الشریعہ اکادمی کی ترقی کے لیے دعا مانگی گئی۔
الشریعہ اکادمی میں، اسکول وکالج کے طلبہ کے لیے ترجمہ قرآن کریم وعربی زبان کی نئی کلاس کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کلاس ہر روز بعد از نماز مغرب اکادمی کے زیر انتظام مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں منعقد ہوگی اور اکادمی کے رفیق مولانا حافظ محمد رشید تدریس کے فرائض انجام دیں گے۔ ان شاء اللہ العزیز
ہیپا ٹائٹس کی تباہ کاریاں
حکیم محمد عمران مغل
ہیپا ٹائٹس کا اژدہا منہ کھولے اور پھن پھیلائے سارے ملک میں تباہی پھیلا رہا ہے، حتیٰ کہ سرسبز مقامات کے علاوہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہائش پذیر آبادی بھی اس کے چنگل سے محفوظ نہیں۔ مریضوں کی بدپرہیز اور معالجوں کی ناسمجھی نے نوبت جگر کی پیوند کاری تک پہنچا دی ہے۔ خدا نخواستہ اتنا مہنگا علاج بھی خاطر خواہ نتائج نہ دے سکا تو کیا ہوگا؟ اطباء عظام نے فرمایا ہے کہ جگر سے کتنا بھی خلاف فطرت کام لیا جائے، یہ کام کرتا رہے گا اور ایک عرصہ تک خراب نہیں ہوگا، لیکن جتنا وقت خراب ہونے میں لے گا، اتنا ہی ٹھیک ہونے میں بھی لے گا۔ ایک بار جگر خراب ہو جائے تو بارہ سال تک اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔
تین تین ماہ کے کورس اور درجنوں انجکشن لگوانے کے باوجود فائدہ نہ ہونے کے مقابلے میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ اطباء نے فقط تین چار دن میں جگر کے مریض کو گھوڑے کے ساتھ دوڑایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھانے والوں نے طب مشرق صحیح معنوں میں پڑھائی اور پڑھنے والوں نے پڑھی ہو۔ ہیپا ٹائٹس سی کی ایک مریضہ،جو دو بچوں کی ماں تھی، کھانے پینے اور چلنے پھرنے اور بولنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ لاہور کے نامور معالجین کے علاج کے باوجود حالت ناگفتہ بہ تھی۔ اس کے میاں ہنڈا کمپنی، جاپانی برانچ، ملتان روڈ لاہور میں مکینک ہیں۔ سبزہ زار پارک میں، میں بھی ان کے گھر کے قریب ایک مدرسہ میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن مریضہ کے شوہر انور صاحب نے روتے ہوئے مدرسہ کے قاری صاحب سے کہا کہ اہلیہ کے علاج میں جائیداد، گاڑی، قیمتی برتن اور گھر کا اثاثہ بیچ چکا ہوں۔ اب خالی ہاتھ ہوں۔ معالجین نے میری بیوی کے ہیپا ٹائٹس سی کو ناقابل علاج قرار دیا ہے۔ قاری صاحب انھیں میرے پاس لے آئے۔ میں نے مریضہ کا باقی علاج جو کچھ کیا، وہ تو اپنے موقع پر عرض کروں گا، انوکھی بات یہ تھی کہ جون جولائی کی گرمی میں اسے کمرے سے باہر نہ لانے کی ہدایت تھی۔ طب مشرق کا اپنا اصول علاج ہے، جیسے کینسر کے مریض کو روزانہ دس بارہ پاخانے آنے چاہییں۔ اسی طرح دیگر امراض میں بخار، کھانسی، نزلہ، زکام، پیچش کا ہونا صحت کے لیے لازمی ہے۔ میرے علاج سے صرف دو ماہ میں مریضہ بارہ سال کی بچی کی طرح اچھلنا کودنا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب اس کی دیکھی ہوئی صورت پہچانی نہیں جاتی تھی۔
ان شاء اللہ اس مرض پر مزید تفصیل نسخہ جات کے ساتھ عرض کروں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہیپا ٹائٹس سی طب مشرق میں قطعی طور پر قابل علاج ہے۔ کسی آپریشن کی قطعاً ضرورت نہیں۔
جون ۲۰۱۱ء
اسامہ بن لادنؒ اور ان کی جدوجہد
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(نائن الیون کے فوراً بعد ’’الشریعہ‘‘ کے رئیس التحریر مولانا زاہد الراشدی نے ایک سوال نامہ کے جواب میں معروضی صورت حال کے تجزیے کے حوالے سے ایک تحریر قلم بند کی تھی جو ’’جہادی تحریکات اور ان کا مستقبل‘‘ کے زیر عنوان ’الشریعہ‘ کے جنوری ۲۰۰۲ء کے شمارے میں شائع ہوئی۔ موجودہ صورت حال کی مناسبت سے یہ تحریر یہاں دوبارہ شائع کی جا رہی ہے۔ مدیر)
سوال :۱۱ ستمبر کے حملے کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
جواب : ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر اور واشنگٹن میں پنٹاگون کی عمارت سے جہاز ٹکرانے کے جو واقعات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں حتمی طور پرکچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نے کیے ہیں اور خود مغربی ایجنسیاں بھی اس سلسلے میں مختلف امکانات کا اظہار کر رہی ہیں لیکن چونکہ امریکہ ایک عرصہ سے معروف عرب مجاہد اسامہ بن لادن اور عالم اسلام کی مسلح جہادی تحریکات کے خلاف کارروائی کا پروگرام بنا رہا تھا اور خود اسامہ بن لادن کی تنظیم ’’القاعدہ‘‘ کی طرف سے امریکی مراکز اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کے اعلانات بھی موجود تھے اس لیے امریکہ نے ان حملوں کا ملزم اسامہ بن لادن کو ٹھہرانے اور افغانستان کی طالبان حکومت سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فوری مطالبہ کر دیا اور اقوام متحدہ اور ورلڈ میڈیا کے ذریعے سے وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش میں لگ گیا کہ ان حملوں کی ذمہ داری اسامہ بن لادن پر ہی عائد ہوتی ہے۔
جہاں تک ان حملوں کا تعلق ہے، دنیا کے ہر باشعور شخص نے ان کی مذمت کی اور ان میں ضائع ہونے والی ہزاروں بے گناہ جانوں کے نقصان پر افسوس اور ہم دردی کا اظہار کیا ہے لیکن امریکہ نے ا س پر جس رد عمل کا اظہار کیا اور اس رد عمل پر اپنے آئندہ اقدامات کی بنیاد رکھی، اس کے بارے میں واضح تاثر یہ تھا کہ اس رد عمل کی بنیاد حوصلہ وتدبر پر نہیں بلکہ غصے اور انتقام پر ہے اور عام طور پر یہ محسوس ہونے لگا کہ امریکہ بہر صورت فوری انتقامی کارروائی کرنے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ’’جہادی تحریکات‘‘ کو کچل دینے پر تل گیا ہے اور اس کے بعد ہونے والے مسلسل اقدامات نے اس عمومی تاثر واحساس کی تصدیق کر دی ہے۔
جہاں تک الشیخ اسامہ بن لادن اور افغانستان کی طالبان حکومت کے موقف کا تعلق ہے، ان کے طریقہ کار اور ترجیحات سے اختلاف کی گنجائش کے باوجود اصولی طور پر ان کا موقف درست تھا اور امریکہ کا موقف اس کے مقابلے میں کمزور اور بے وزن تھا، اسی لیے امریکہ نے کارروائی میں عجلت سے کام لیا تاکہ ۱۱ ستمبر کے واقعات کے نتیجے میں اسے عالمی سطح پر جو ہم دردی حاصل ہوئی ہے، ا س کے ٹھنڈا پڑ جانے سے قبل وہ سب کچھ کر دیا جائے جس کے لیے امریکی دماغ اور ادارے کئی سال سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسامہ بن لادن روس کے خلاف ’’جہاد افغانستان‘‘ میں عملاً شریک تھے اور امریکہ بھی اس جہاد کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، اسی لیے اس دور میں مغربی ذرائع ابلاغ اور خود امریکی ادارے انہیں ایک ’’عظیم مجاہد‘‘ کے طور پر پیش کرتے رہے اور جہاد افغانستان کے خاتمے کے بعد اسامہ بن لادن ایک ہیرو کے طو رپر اپنے وطن واپس جا چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خود ان کے اپنے ملک سعودی عرب اور اس کے ساتھ پورے عرب خطے کو امریکہ کے ہاتھوں وہی صورت حال درپیش ہے جو جہاد افغانستان سے قبل افغانستان کو روس کے ہاتھوں درپیش تھی تو ان کے لیے اس صورتِ حال کو قبول کرنا ممکن نہ رہا۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیج عرب میں امریکی فوجیں مسلسل بیٹھی ہیں جس کی وجہ سے عرب ممالک کی آزادی اور خود مختاری ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ عرب ممالک کی دولت اور تیل کا بے دردی کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے، عرب عوام کو انسانی، شہری اور شرعی حقوق حاصل نہیں ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا کوئی موقع بھی میسر نہیں ہے جبکہ فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور تشدد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور فلسطینی عوام پر ان کی اپنی زمین تنگ کر دی گئی ہے تو انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور مطالبہ کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجیں خلیج عرب سے نکل جائیں، لیکن چونکہ ان کے ملک میں اس قسم کی بات کہنے اور کوئی سیاسی مہم چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے انہیں مجبوراً اس رخ پر آنا پڑا کہ وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کریں اور خلیج عرب سے امریکی فوجوں کی واپسی کے لیے اسی قسم کی جدوجہد منظم کریں جس طرح کی جدوجہد کا تجربہ افغانستان سے روسی فوجوں کی واپسی کے لیے اس سے قبل ہو چکا تھا اور وہ خود اس میں شریک رہے تھے۔
اسامہ بن لادن کے طریق کار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کا موقف اور مطالبہ اصولی طور پر درست تھا اور اس بات سے اختلاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ سعودی عرب اور خلیج عرب کے دیگر ممالک میں سیاسی جدوجہد کے راستے مکمل طور پر مسدود ہونے کی وجہ سے اسامہ بن لادن اور ان کے رفقا کے لیے اپنے جذبات اور موقف کے اظہار کے لیے صرف ایک راستہ باقی رہ گیا تھا جسے تشدد کا راستہ کہا جاتا ہے اور جس پر اسامہ بن لادن کو مطعون کیا جاتا ہے، لیکن طعن وتشنیع کرنے والے اس معروضی تناظر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ان حالات میں ان کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔
اسامہ بن لادن کا خیال تھا کہ وہ جہاد افغانستان میں ٹریننگ لینے والے دنیا بھر کے مجاہدین کو ایک نظم اور پروگرام میں منسلک کریں گے اور اس طرح ایک ایسا مزاحمتی گروپ وجود میں آجائے گا جو عالم اسلام کے مختلف حصوں میں ہونے والے جبر وتشدد کے خلاف ’’پریشر گروپ‘‘ کا کام کرے گا اور شاید وہ اس کے ذریعے سے اسرائیلی جارحیت کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے اور خلیج عرب میں امریکی فوجوں کے خلاف اس حد تک دباؤ منظم کرنے میں کام یاب ہو جائیں جو امریکہ کو خلیج عرب میں اپنی فوجوں کی موجودگی کے تسلسل پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سوڈان کو اپنی سرگرمیوں کامرکز بنایا لیکن امریکی دباؤ کی وجہ سے سوڈان کی حکومت کے لیے اسامہ بن لادن کا وجود برداشت کرنا ممکن نہ رہا چنانچہ وہ سوڈان چھوڑ کر افغانستان آ گئے جہاں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور وہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے قیام اور امریکہ کے تسلط سے عالم اسلام بالخصوص خلیج عرب کی آزادی کے حوالے سے اسامہ بن لادن کے موقف سے متفق تھی۔ ان کے ساتھ وہ ہزاروں عرب مجاہد بھی افغانستان آ گئے جو جہاد افغانستان میں شریک تھے اور اسلامی جذبات سے سرشار ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے ملکوں میں واپس جانے کی صورت میں حکومتوں کی طرف سے انتقامی کارروائیوں اور ریاستی جبر کا نشانہ بننے کے خطرات سے دوچار تھے۔
طالبان حکومت نے نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ موقف اور جذبات کی ہم آہنگی اور دینی حمیت میں شراکت کی وجہ سے دونوں میں ایسے تعلقات کار بھی قائم ہو گئے کہ انہیں ایک ہی منزل کے مسافر سمجھا جانے لگا۔ اس کے باوجود طالبان حکومت نے ۱۱ ستمبر کے واقعات کے بعد یک طرفہ موقف اختیار نہیں کیا بلکہ ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر ثبوت فراہم کر دیے جائیں تو وہ اسامہ بن لادن کو حوالے کر دینے کے مطالبے پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں یا کسی ایسے بین الاقوامی فورم کے حوالے بھی کر سکتے ہیں جو غیر جانب دار ہو مگر امریکہ نے رعونت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کے اس جائز موقف کو مسترد کر دیا اور اپنے الزامات کو ہی قطعی ثبوت قرار دیتے ہوئے افغانستان پر حملہ کا اعلان کر دیا جس کے ذریعے سے امریکہ نے وہ دونوں مقاصد حاصل کر لیے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھے تھے اور ۱۱ ستمبر کے واقعات ان کے لیے محض بہانہ ثابت ہوئے۔
سوال : افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جواب : طالبان حکومت قائم ہوتے ہی مجھے یہ خدشہ محسوس ہونے لگا تھا اور میں نے کئی مضامین میں اس کا اظہار بھی کیا کہ اس حکومت کو برداشت کرنا نہ صرف یہ کہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان حکومتیں بھی اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں جو اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کے نفاذ کی تحریکات کا سامنا کر رہی ہیں کیونکہ طالبان حکومت کی کامیابی کا واضح مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان ملکوں میں اسلامی نظام کے نفاذ کی تحریکات کو تقویت حاصل ہوتی اور ایک کام یاب حکومت کی صورت میں عملی آئیڈیل بھی مل جاتا۔ اس لیے امریکہ اور کفر کی دیگر طاقتوں کے ساتھ ان مسلم حکومتوں کا اتحاد ایک فطری بات تھی اور ان سب نے مل کر ایک ایسی حکومت کو ختم کر دیا ہے جو اپنی کام یابی کی صورت میں دونوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ خطرہ اس معنی میں نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی قوت ہوتی بلکہ اس معنی میں کہ موجودہ عالمی سسٹم سے ہٹ کر اور اس سے بغاوت کر کے ایک الگ نظریہ اور فلسفہ کے تحت بننے والی کسی حکومت کی کام یابی سے ان تمام قوتوں اور عناصر کو بغاوت کا راستہ مل جاتا جو موجودہ عالمی سسٹم سے مطمئن نہیں ہیں اور ا س سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسے بہت بڑ اخطرہ سمجھا گیا اور اسے ختم کرنے پر دنیا کی سب حکومتیں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود متفق ہو گئیں۔
امریکہ اور اس کی زیر قیادت عالمی استعمار کو عالم اسلام سے کوئی فوجی، سیاسی یا معاشی خطرہ نہیں ہے اور نہ مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان ہی ہے بلکہ فوجی، سیاسی اور معاشی طور پر پور اعالم اسلام امریکہ کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا ہوا ہے مگر مغربی تہذیب وثقافت اور فلسفہ ونظام کے مقابلے میں اگر کسی فلسفہ ونظام اور تہذیب وثقافت میں کھڑا ہونے کی قوت وصلاحیت موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی اسلامی تحریکات کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں اور بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس فلسفہ ونظام اور تہذیب وثقافت کو اگر دنیا کے کسی خطے میں ایک ریاستی سسٹم کے طور پر قدم جمانے کا موقع مل گیا تو وہ موجودہ عالمی نظام اور مغربی فلسفہ وثقافت کے لیے حقیقی خطرہ بن سکتا ہے اسی وجہ سے موجودہ عالمی سسٹم کے ارباب حل وعقد نے قطعی طور پر یہ بات طے کر رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسی مسلمان حکومت وجود میں نہ آنے پائے جو موجودہ عالمی سسٹم اور بین الاقوامی نیٹ ورک سے ہٹ کر ہو یا دوسرے لفظوں میں اقوام متحدہ کی بالادستی قبول کرنے کے بجائے وہ اپنا کوئی الگ ایجنڈا رکھتی ہو۔ افغانستان میں طالبان کی اسلامی نظریاتی حکومت کو تسلیم نہ کرنے اور اب اسے فوجی طاقت کے زور پر ختم کر دینے کا بھی یہی پس منظر ہے البتہ طالبان حکومت کے خاتمے پر انتہائی افسوس اور صدمہ کے باوجود کسی حد تک یہ بات اطمینان بخش ہے کہ طالبان حکومت کا خاتمہ فلسفہ ونظام اور تہذیب وثقافت میں مغرب کی بالادستی کے حوالے سے نہیں ہوا بلکہ محض مادی طاقت، جبر وتشدد اور عسکری قوت کے زور پر اسے ہٹایا گیا ہے۔ فکر وفلسفہ اور نظام وثقافت اگر زندہ ہوں تو عسکری ناکامیاں زیادہ دیر تک ان کا راستہ نہیں روک سکتیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے اظہاراور پیش قدمی کے راستے نکال لیا کرتے ہیں۔
سوال :مستقبل میں افغانستان کی صورت حال کیا ہوگی؟
جواب : میرے خیال میں امریکی اتحاد کی پشت پناہی سے قائم ہونے والی حکومت افغانستان میں امن قائم کرنے میں کام یاب نہیں ہوگی اور افغانستان کے سب قبائل کو مطمئن کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ صرف اسلام اور ایمان کی قوت تھی جس نے قبائلی تعصبات اور علاقائی امتیازات کو دبارکھا تھا۔ اس کا پردہ ہٹ جانے کے بعد اب تمام معاملات قبائل اور علاقائیت کے حوالے سے طے پائیں گے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان عصبیتوں میں اضافہ ہوگا جبکہ مغربی قوتوں کا مفاد بھی اسی میں ہوگا کہ یہ عصبیتیں بڑھیں اور اختلافات وتفرقہ کا ماحول قائم رہے تاکہ وہ اس کی آڑ میں افغانستان پر اپنا کنٹرول زیادہ دیر تک قائم رکھ سکیں اور وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کر سکیں۔
دوسری طرف طالبان تحریک نے میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی ہے، ذہنی طور پر شکست اور دست برداری قبول نہیں کی اور ان کی افرادی قوت بڑی حد تک محفوظ ہے اس لیے وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ منظم ہوں گے اور مزاحمت کا راستہ اختیار کریں گے جس کی حمایت وتعاون کرنا اس خطے کی ان تمام قوتوں کی مجبوری بن جائے گا جو امریکہ کی یہاں مستقل موجودگی کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ وقتی لشکر کشی میں امریکی اقدامات کا ساتھ دینا اور بات ہے اور اس خطے میں امریکہ کی مستقل فوجی موجودگی کو قبول کرنا اس سے بالکل مختلف امر ہے اس لیے اس کا فائدہ ہر اس قوت کو ہوگا جو افغانستان میں امریکی اتحاد کی فوجوں کی مستقل یا زیادہ دیر تک موجودگی کے خلاف مزاحمت کا راستہ اختیار کرے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ طالبان کی یہ مزاحمتی تحریک دوبارہ منظم ہونے میں ایک سال اور اپنے ہدف تک پہنچنے میں پانچ چھ سال کا عرصہ لے سکتی ہے اور افغان قوم کے مزاج، روایات اور تاریخی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اس کی کام یابی میں شک اور تردد کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔
سوال :القاعدہ اور طالبان کو نشانہ بنا کر امت مسلمہ پر جو ظلم کیا گیا ہے، اس میں اسلامی ممالک کی کیا ذمہ داری ہے؟
جواب : میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ مسلم حکومتیں عالمی نظام اور اقوام متحدہ کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، وہ ا س سے بغاوت اور انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتیں اس لیے ان سے کسی ذمہ داری کی ادائیگی بلکہ کسی بھی درجے میں کسی خیر کی توقع کرنا ہی فضول ہے۔ اسلامی تحریکات کو مسلم عوام سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا اور انہی کے اعتماد اور تعاون سے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اس کے سوا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔
سوال:مستقبل میں مجاہدین کو کس طرح کا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بالخصوص اب جبکہ پاکستان میں بھی مجاہدین کے خلاف عملی کارروائی ہونے کی توقع ہے؟
جواب : میں اصولی طور پر تشدد کے حق میں نہیں ہوں اور پر امن سیاسی جدوجہد کا قائل ہوں، اسی وجہ سے جہاں سیاسی جدوجہد کے راستے کھلے ہوں، وہاں کسی قسم کی پر تشدد تحریک کو جائز نہیں سمجھتا اور پاکستان میں بھی نفاذ اسلام کی جدوجہد کے لیے تشدد اور عسکریت کا راستہ اختیار کرنا میرے نزدیک درست طرز عمل نہیں ہے البتہ جہاں عالمی جبر یا ریاستی تشدد کی فضا موجود ہو اور اس کے خلاف رائے عامہ کو منظم کرنے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور سیاسی دباؤ ڈالنے کے تمام راستے مسدود ہوں، وہاں احتجاج کرنے اورکلمہ حق بلند کرنے والوں کی طرف سے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کو ان کی مجبوری سمجھتا ہوں اور مجبوری ہی کے درجے میں ان کی حمایت کو دینی حمیت کا تقاضا تصور کرتا ہوں۔ اسی طرح جن غیر مسلم ممالک میں مسلم اکثریت کے خطے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی جدوجہد میرے نزدیک جہاد ہے۔ اس پس منظر میں ’’جہادی تحریکات‘‘ کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ مل بیٹھ کر اپنی پالیسی اور طریق کار کا ازسر نو جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کی نشان دہی کریں، ترجیحات پر نظر ثانی کریں اور اہل علم ودانش کو اعتماد میں لے کر اپنا آئندہ طرز عمل طے کریں۔
میرے نزدیک جن باتوں نے جہادی تحریکات کو نقصان پہنچایا ہے، ان میں چند اہم امور یہ ہیں:
۱۔ اصل اہداف سے ہٹ کر جذباتی نعرہ بازی مثلاً دہلی کے لال قلعہ پر جھنڈا لہرانے، پاکستان میں طالبان کی طرز پر انقلاب لانے اور مغربی ملکوں کے مراکز کو نشانہ بنانے کی باتیں جنہوں نے ان سب قوتوں کو نہ صرف چوکنا کیا بلکہ متحدبھی کر دیا۔
۲۔ ایجنسیوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اختلاط اور اس اختلاط میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی درپردہ کوششیں جن کی وجہ سے پالیسی سازی اور فیصلوں کی قوت بتدریج جہادی تحریکات کی لیڈرشپ کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔
۳۔ باہمی مشاورت، تعلقات کار اور انڈر سٹینڈنگ کے ضروری اہتمام سے گریز۔
۴۔ ملک کے داخلی معاملات بالخصوص فرقہ وارانہ امور میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ملوث ہونا۔
۵۔ اور اہل علم ودانش سے صرف تعاون اور سرپرستی کے حصول پر قناعت کرتے ہوئے ان سے راہ نمائی اور مشاورت کی ضرورت محسوس نہ کرنا۔
یہ اور اس قسم کی دیگر کئی باتیں ہیں جنہوں نے جہادی تحریکات کو نقصان پہنچایا اور ان کے مخالف عناصر کو اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے، اس لیے جہادی تحریکات کو اپنی پالیسیوں اور طریق کار کا ازسرنو جائزہ لینا چاہیے اور اہل علم ودانش کی راہ نمائی میں لائحہ عمل اور ترجیحات کا پھر سے تعین کرنا چاہیے۔
قومی خودمختاری کا سوال اور ہماری سیاسی قیادت
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
مسلسل ڈرون حملوں نے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی خود مختاری پر پہلے ہی سوالیہ نشان لگا رکھا تھا، مگر شیخ اسامہ بن لادن شہیدؒ کے حوالہ سے ’’ایبٹ آباد آپریشن‘‘ نے اس سوال کے سوالیہ پہلو کو اور زیادہ تاریک کر دیا ہے اور پوری قوم وطن عزیز کی خود مختاری کی اس شرم ناک پامالی پر چیخ اٹھی ہے۔ پوری قوم مضطرب ہے، بے چین ہے اور ایک ’’اتحادی‘‘ کی اس حرکت پر تلملا رہی ہے، مگر حکومتی پالیسیوں کے تسلسل میں کوئی فرق دیکھنے میں نہیں آ رہا اور وہ پالیسیاں جن کو ملک کے عوام نے گزشتہ الیکشن میں کھلے بندوں اپنے ووٹوں کے ذریعے مسترد کر دیا تھا او رمنتخب پارلیمنٹ نے بھی متفقہ قرارداد کی صورت میں ان پالیسیوں سے بے زاری کا اظہار کر دیا تھا، پرویز مشرف کے وہ معاہدات اورپالیسیاں آج بھی نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان پر عمل درآمد کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
قوم کے اضطراب اور غصے کو پارلیمنٹ کی ایک اور ’’متفقہ قرارداد‘‘ کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر اس قرارداد کا مستقبل بھی سابقہ قرارداد سے مختلف دکھائی نہیں دے رہا۔ اصل بات قراردادوں اور اخباری بیانات کی نہیں، بلکہ پالیسیوں اور خفیہ معاہدات کی ہے۔ جب تک ان پر نظر ثانی نہیں ہوتی اور قومی مفادات اور عوامی جذبات کے مطابق ان سے ’’یوٹرن‘‘ لینے کی کوئی سبیل سامنے نہیں آتی، تب تک ان قرادادوں اور اخباری بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ اب تو یہ بیانات اور قراردادیں قوم کے ساتھ مذاق کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔
شیخ اسامہ بن لادن تو شہید ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائے کہ وہ شہادت ہی کی تمنا رکھتے تھے، مگر ان کے ساتھ ہماری قومی خود مختاری بھی شہید ہو گئی ہے۔ یہ بات ہماری قومی سطح کی سیاسی ودینی قیادت کے لیے لمحہ فکریہ ہے بلکہ نشان عبرت ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:
وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِیْنَ نَسُوا اللَّہَ فَأَنسَاہُمْ أَنفُسَہُمْ (الممتحنہ: ۱۹)
’’ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنھوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔‘‘
قوموں کا اپنے نفع ونقصان سے غافل ہو جانا اور قومی قیادتوں کا ملی جذبات ومفادات سے بے پروا ہو جانا ’’عذاب خداوندی‘‘ ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت بتاتی ہے کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کی حالت کا ادراک کریں، اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اپنے خالق ومالک کو یاد کرنے کا ذوق زندہ کریں اور بارگاہ ایزدی میں توبہ واستغفار کا اہتمام کریں تاکہ ’’خود سے غافل ہو جانے‘‘ کے اس قومی عذاب سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سطح پر اس کا احساس وادراک اور اصلاح احوال کی توفیق سے نوازیں۔ آمین یا رب العالمین
اُسامہ
خورشید احمد ندیم
یہ خبر نہیں، اداسی کی ا یک لہر تھی جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔پہلا ردِ عمل ایک جملہ تھا: اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ایک دنیامدت سے موت بن کراُس کی تلاش میں تھی۔ تورہ بورہ کا مقتل، افغانستان کے صحرا، پاکستان کی وادیاں، کہاں کہاں اُس کا پیچھا نہیں کیا گیا۔لیکن اسے کب اور کہاں مر ناہے، یہ صرف عالم کا پروردگار جانتا تھا۔اِس کی خبرتو اس نے پیغمبروں کو بھی نہیں دی۔ وہ وقت آیا تو اسامہ کو مو ت کے حوا لے کر دیا گیا۔ لا ریب، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف لو ٹنا ہے۔
موت کسی کی بھی ،مجھے اداس کر دیتی ہے۔ اِس مو ت کی اداسی مگر دوگنا تھی۔ ایک اس کا رنج کہ ایک مسلمان مارا گیا۔ دوسرا اس کا دکھ کہ ایسے عزم اور حو صلے والا، اگر اپنی صلاحیتوں کو اس امت کی فلاح کے لیے صرف کر دیتا تو اس زمین کے کتنے صحراؤں کو گلزار بنا سکتا تھا۔ جس نے امریکا کو چیلنج کیا، اگر پہلے ہمارے افلاس کو مخاطب بنا تا توہم اغیار کی دریوزہ گری سے نکل آتے۔ اگر ہماری جہالت کو اپنا ہدف بناتا تو دنیا طلب علم کے لیے واشنگٹن اور کیمبرج کے بجائے کابل اور اسلام آ باد کا رخ کر تی۔ جب ہم علم اور ما دی وسائل میں خود کفیل ہو تے توغلامی کی زنجیریں ٹو ٹتیں۔ ہم اپنے فیصلے خود کر تے اور ہمارے شہر قتل گاہوں میں تبدیل نہ ہو تے۔ جو امریکا کے خلاف جہاد کے لیے ایک ولولہ تازہ دے سکتا تھا، وہ جہالت ا ور غربت کے خلاف جہاد کے لیے بھی مجاہدین کے لشکر تیا رکر سکتا تھا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ صرف افغانستان ہی اگر تعمیر کا نمو نہ بن جاتا تو ہم دنیا کو دکھاتے کہ مسلمان کس طرح ایک نئی دنیا کی تعمیر کا سلیقہ رکھتے ہیں۔صد افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ میرے لیے یہ ایک مسلمان بھائی کی موت ہی نہیں، ایک ایسے حو صلے کی بھی موت ہے جو بد قسمتی سے مسلمانوں اور دنیا کے لیے تباہی کا پیغام بن گیا۔
اسا مہ رخصت ہو ئے۔اب ان کا معا ملہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ لیکن وہ ہمارے لیے بہت سے سوال چھوڑ گئے، ہمیں جن کے جواب تلاش کر نے ہیں۔ یہ سوال ہیں کیا؟
- عہدِ حاضر میں اگر مسلمانوں کو وقار کے ساتھ جینا ہے تواس کی حکمتِ عملی کیا ہو نی چا ہیے؟
- علم کے بغیر، جس کا ایک مظہر سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت ہے، کیا کو ئی معر کہ سر کیا جا سکتا ہے؟
- اگر امریکا بطور عالمی قوت ختم ہو جا ئے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہمارے لیے کو ئی نیا سامراج وجود میں نہیں آئے گا؟
- اس دور میں جارح کے خلاف جنگ کیا محض جذبے کے ساتھ جیتی جا سکتی ہے جب کہ وسائل میں غیر معمولی فرق ہو؟
- اس عسکریت پسندی نے ہمیں کیا دیا؟ مسلمان ملکوں کو مقتل بنانے میں اس سوچ کا کتنا دخل ہے اور کیا یہ کو ئی کامیابی ہے؟
- اگر اس مہم جو ئی کے نتیجے میں ایک مسلمان بھی بے گناہ مارا گیا تو اس کی جان کا وبال کس کے سر ہے؟ کیا ہمارے پاس کو ئی ایسا جواب مو جود ہے جو ہم اپنے رب کے حضور میں پیش کر سکیں؟
- ۱۱/۹ کے بعد مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے اور امریکا کا کتنا؟
- کیا القاعدہ اور بلیک واٹر کی سر گرمیوں کے مابین کوئی واضح حدِ فاصل تلاش کی جا سکتی ہے؟تحریک طالبان پاکستان کیا ہے؟ القاعدہ، بلیک واٹر یا ایک واہمہ؟
- کیا ہم کسی دوسری ایسی مزاحمتی تحریک کا تصور کر سکتے ہیں جس کی بنیاد مسلمان معا شروں کی تعمیر ہو اور جس میں خسارہ نہ ہو نے کے برابر ہو، تاہم اس کے نتیجے میں ہم اغیار کے اثرو رسو خ کا خاتمہ کر سکیں؟
ہم نہیں جا نتے کتنے باعزم اور حو صلے والے جوان اب بھی اس راستے پر چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں امریکی وحشت اور بربریت سے بچا نا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کو امت کے لیے مفید بنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سوالات پر غور کیا جائے اور ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس میں ہمارے قیمتی لوگ محفوظ رہیں اور ہم ان کی صلاحیتوں سے بہتر فائدہ اٹھاسکیں۔
مجھے دکھ اس کا بھی ہے کہ ایک مسلمان کی جا ن ہی نہیں گئی، اس کے ساتھ ہمارے اس اعتبار کا جنازہ بھی اٹھ گیا جو ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے دنیا میں ہماری پہچان ہو نا چا ہیے تھا۔ ہم بر سوں سے ساری دنیا کو یہ کہتے رہے کہ اسامہ یا ان سے متعلق لوگ پاکستان میں نہیں ہیں۔ اب ایک تو امریکیوں نے اسامہ کو ہماری سر زمین سے تلاش کر لیا اور دوسرا یہ کہ ہماری مکمل لا علمی میں انہوں نے عین ہماری ناک کے نیچے ایک آ پر یشن کیا اور ہم بے خبر رہے۔ جب امریکی یہ آپریشن کر رہے تھے، ہماری فوج کے سپریم کمانڈر اور صدر مملکت سیاسی جو ڑ توڑ میں مصروف تھے جب کہ ہمارے سپہ سالار بھی اسی سیاسی قضیے میں کسی دوسرے کا دکھڑا سن رہے تھے۔ اب ایک طرف عالمی برادری میں ہمارا وقار شکوک کی زد میں ہے اور دوسری طرف بیرونی جا رحیت سے محفوظ رکھنے کی ریاستی صلاحیت کے بارے میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ معمولی صدمہ نہیں اور اس سے میرے دکھ میں تشویش بھی شامل ہو گئی ہے۔
زندہ افراد کی نشانی یہ ہے کہ وہ حادثات سے سیکھتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ،نہ تو اچانک ہوا اور نہ ہی یہ غیر متوقع تھا۔ اس کالم میں بار ہا اس کی طرف تو جہ دلا ئی جاتی رہی۔مجھے یہ زعم نہیں کہ پالیسی ساز اس کالم سے کو ئی راہنمائی لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو زبر دستی مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو تاریخ کے سامنے اپنی گواہی پیش کر دیتے ہیں۔یہ رب کے حضور میں ہماری معذرت ہو گی کہ ہم نے جو سمجھا ،اس کے مطابق لوگوں کو خبر دار کر دیا اور یوں بساط بھر ’انذار ‘ کا فریضہ سر انجام دیا۔آج ایک بار پھر میں نے یہ اپنا دکھ ریاست کے ذمہ دار ان اور فکرِ اسامہ کے متاثرین کے سامنے رکھ دیاہے۔یہ ایک عجیب کیفیت کا اظہار ہے جب دکھ اور تشویش باہم گلے مل رہے ہیں۔ دکھ اس کا کہ اسامہ جیسا حو صلہ مند ایک فکری غلطی کی نذر ہو گیا اور تشویش اس کی کہ عالمی سطح پر ہمارے وقار کا کیا ہوگا۔اگر ہمارے اربابِ حل وعقد اور احیائے امت کے علمبرداروں نے اب بھی اپنی سوچ پر نظر ثانی نہ کی تو اس امت کا کیا بنے گا؟ اھدنا الصراط المستقیم!
(بشکریہ روزنامہ اوصاف)
گوجرانوالہ میں توہین قرآن کا واقعہ: چند حقائق
چوہدری محمد یوسف ایڈووکیٹ
ہمارا محلہ کھوکھر کی گوجرانوالہ کا بہت پرانا محلہ ہے۔ یہاں عیسائی اور مسلم آبادی باہم شیر وشکر رہتی ہے۔ سیالکوٹ روڈ کے پار عیسائیوں کے بڑے بڑے عبادت خانے موجود ہیں۔ عیسائی مسلم کشیدگی کی صورت کبھی سننے میں نہیں آئی۔ انٹر نیٹ پر عیسائی زعما نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس محلے اور اس کی مضافات (عزیز کالونی، گلزار کالونی، اسلام کالونی) میں ایک سو پچیس سال سے عیسائی اور مسلمان بھائیوں کی طرح پر امن رہ رہے ہیں۔ یہاں عیسائی خاندانوں کی تعداد تین ہزار بیان کی جاتی ہے۔ وہ پر امن رہے ہیں اور امن و امان کی چادر تلے خوش و خرم ہیں۔ کبھی انتظامی بے اعتدالی ہوئی بھی تو مسیحی برادری نے درگذر سے کام لیا۔ اس کی مثال پچھلے دنوں سیالکوٹ روڈ کو کشادہ کرنے کے لیے تجاوزات گرانے کی مہم کے دوران سامنے آئی۔ اس مہم میں گرجا گھروں اور مشنریوں کے دیگر اداروں نے تجاوزات کو، رضاکارانہ طور پر خالی کیا۔ مگر صد افسوس، سیشن کورٹ کے مین دروازے کے بالمقابل، کھو کھر کی کا پرانا قبرستان اور اس کے کونے پر واقع مسجد انصاف کا منہ چڑا رہی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کے قبرستان اور مسجد کو سڑک کی حدود سے ہٹانے میں پہل کی جاتی، پھر عیسائیوں کے معبدوں کو چھیڑا جاتا۔ بلا شبہہ انتظامیہ نے یہاں کمزوری دکھائی اور مسلمانوں کو اپنے تجاوزات ہٹانے کے لیے مہلت دے دی۔ اس انتظامی بے انصافی پر عیسائی کمیونٹی نے در گزر سے کام لیا۔ اگر اسے تنازع بنایا جاتا تو معاملہ دور تک جا سکتا تھا۔
مسلمانوں کے علما بالعموم انتظامیہ سے ساز گاری رکھتے ہیں۔ اگر انتظامیہ انصاف پر مبنی طرز عمل اختیار کرتی تو میرے نزدیک علما کی جانب سے مشکلات پیدا نہ کی جاتیں۔ یہاں میں راستے میں واقع مسجد اور مسلمانوں کے قبرستان کا ذکر، عیسائیوں کی نظر میں نمبر گیم کے لیے نہیں کر رہا۔ اس متجاوز مسجد اور قبرستان کے قریب سے دن میں کئی بار گزرنا پڑتا ہے ۔ اس طرح یہ منظر مجھے ہر بار کھٹکتا ہے۔
محلہ میں رہتے ہوئے بھی اکثر مجھے کئی بڑے بڑے واقعات کا کافی بعد میں علم ہوتا ہے۔ عام روایت ہے کہ تھانے میں درج ابتدائی رپورٹ کے مطابق قرآن حکیم کے اوراق کی بے حرمتی اور توہین رسالت کا الزام ایک شخص انور مسیح گل پر عائد کیا گیا۔ انٹر نیٹ کی رپورٹ کے مطابق اس کیس میں مشتاق گل اور اس کا بیٹا فرخ مشتاق بھی گرفتار ہوا۔ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سخت اشتعال انگیز تھا۔ احتجاج شروع ہوا۔ قبا مسجد وقوعہ کے قریب ترین جامع مسجد ہونے کی وجہ سے احتجاج کا مرکز بنی۔ مسجد کے خطیب و متولی سید عرفان شاہ احتجاجی تحریک کے قائد ہوئے۔ ان کے جمعہ کے خطابات بڑے متوازن تھے۔ امن میں خلل ڈالنے کا کوئی عندیہ ان کی جانب سے نہیں تھا۔ وہ بر ملا یہی کہتے رہے کہ وہ پر امن احتجاج کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بار ہا کہا کہ ہم احتجاج کو ہر صورت پر امن اور قانون کے دائرے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ ان کی پر امن ریلیوں میں تخریب کار گھس کر اسے تشدد کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ وہ لوگوں اور انتظامیہ کو اس بارے میں خبر دار کرتے رہے۔ وقوعہ کی نسبت تھانہ جناح روڈ میں رپورٹ ابتدائی ۱۵؍ اپریل ۲۰۱۱ء کو درج ہوئی۔ وقوعہ گزری ہوئی رات کا تھا۔ اگلی صبح سویرے جمعہ کا دن تھا۔ صبح ہوتے ہی اس رو فرسا واقعہ کا لوگوں کے علم میں آیا تو پولیس کو رپورٹ کیاگیا۔ جمعہ ہی سے احتجاج شروع ہوا۔
۲۲؍اپریل ۲۰۱۱ء کو مجھے صورت حال کا علم ایک یارِ مہربان سے ہوا۔ میں ان کے ہمراہ صبح صبح احتجاج کے ذمہ داران سے ملا۔ ان میں عرفان شاہ صاحب شامل تھے۔ مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ ملزم گرفتار تھا۔ تفتیش کا مرحلہ درپیش تھا۔ درج ایف آئی آر نمبر ۱۷۱ کی نقل دکھائی گئی، مگر اس نقل کو کوئی خاص دستاویز کے طور پر مجھے فراہم کرنے سے گریز کیاگیا۔ البتہ ۱۹۲۹ء کی غازی علم الدین شہید والی ابتدائی رپورٹ کی نقل مجھے آسانی سے فراہم کر دی گئی۔ میں نے خود قبا مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ نماز سے پہلے شاہ صاحب کا خطاب جزوی طور پر سنا۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا تھا۔ پھر شاہ صاحب کا جذبات کو آگ لگادینے والا موثر اور ماہرانہ انداز، اپنی جگہ موقعہ کی مناسبت سے کسی طرح بے جوڑ نہیں تھا۔ بڑی مدت کے بعد ایسا منظر دیکھنے کو ملا۔ لوگوں کے جذبات کو زبان دینا لازم تھا اور اس میں ان کے جذبات کو کھولنا کسی لحاظ سے نا مناسب قرار نہیں دیا جاسکتاتھا۔ جذبات کا پرامن طور پر اظہار، خواہ احتجاج کی صورت میں ہو، لوگوں کا حق ہے اور فرض بھی۔ لیکن یہ حق اور فرض، ہر صورت پر امن رہنے کی شرط کے ساتھ منسلک ہے۔
محلے کی مساجد میں جمعہ کا اجتماع اور جمعہ کے خطبات احتجاج کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے۔ علمائے کرام کی جذباتی تقاریر آگ لگا دینے والی تھیں۔ تقاریر کے نتیجہ میں ایک ہی نعرہ لگتا: حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ اس طرح کے قبیح واقعات میں ہر مسلمان کے جذبات ایک جیسے ہی ہیں۔ اس میں کوئی استثنا نہیں۔ کوئی کتنا ہی امن اور اعتدال پسند ہو، اس کی جذباتی کیفیت کسی انتہا پسند سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ سکیورٹی پر متعین افسران سے لے کر معمولی سپاہیوں کی کیفیت بھی یہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے محافظ کے ہاتھوں قتل کی سادہ اور واحد ممکنہ تشریح، اسی سیاق و سباق میں ہو سکتی ہے۔
۲۹؍اپریل کو احتجاجی ریلی نکالنے کے بجائے مسجد کے اندر جلسہ ہوا۔ دیگر مساجد سے آئے ہوئے خطبا نے اپنی تقاریر میں لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی۔ پرنٹ اور اسکرین میڈیا مکمل بائیکاٹ کیے ہوئے تھا۔ عام لوگوں میں چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں کہ بین الاقوامی سطح پر این جی اوز مسیحی برادری کی کھل کر مدد کر رہی ہیں۔ ۲۹ اور ۳۰ کی درمیانی رات کو، اوراق مقدسہ اور رسالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا دوسرا واقعہ سامنے آیا۔ اس کی ایف آئی آر نمبر ۱۸۳ تھانہ جناح روڈ میں درج کی گئی۔ اس پر لوگوں میں پہلے سے پایا جانے والا اشتعال شدت اختیار کر گیا۔ انٹر نیٹ رپورٹ کے مطابق، مقدمہ نمبر ۱۷۱ میں گرفتار ملزمان مشتاق اور فرخ مشتاق کی رہائی بھی اشتعال کا باعث ہوئی۔ ہفتے کا دن تھا۔ جمعہ کے معمول کے اجتماعات کے بغیر ہی لوگ، صبح ہی سے جمع ہونے شروع ہوگئے۔ ایک بڑی ریلی سیالکوٹ روڈ پرپہنچی۔ ٹائروں کو جلا کر سڑک پر دھواں دھواں کر دیا گیا۔ رواں ٹریفک مسدود ہو گئی۔ توڑ پھوڑ کے معمولی واقعات ہوئے۔ بالآخر لوگ چرچ روڈ اور ڈی آئی جی آفس کے سامنے جمع ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چرچ روڈ پر لوگوں نے بعض گرجوں کو جلانے کی کوشش کی۔ علما بھی یہی کہتے ہیں کہ پے درپے واقعات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اشتعال سے یہ رد عمل کچھ زیادہ غیر معمولی نہیں تھا۔ بہر حال انتظامیہ نے نظم عامہ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آنسو گیس کے شیل پھینکے، گرفتاریاں کیں۔ اس کشیدہ صورت حال سے متعلق رپورٹ ابتدائی نمبر ۱۸۴ تھانہ جناح روڈ اور رپورٹ ابتدائی نمبر ۵۲۱ تھانہ سول لائن میں درج کی گئی۔ راتوں رات اڑھائی سو کے لگ بھگ لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ ان میں چھوٹے بچے بھی کافی تعداد میں شامل تھے۔ احتجاج کے قائدین روپوش ہو گئے یا انتظامیہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے کر حالات پر قابو پانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔
اسی دوران روح فرساواقعات کی تفتیش بھی جاری رہی۔ پریس اور ابلاغ عامہ کے دیگر ذرائع قریب قریب خاموش رہے یا خاموش بنا دیے گئے۔ صورت حال کو امن کی جانب گامزن کرنے کے لیے پے درپے اقدامات ہوئے۔ اس میں جماعت اسلامی کی پھرتیاں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھیں۔ کہاں احتجاجی ریلیوں میں اپنی بساط سے بڑھ کر شرکت اور کہاں عیسائی بھائیوں کے ساتھ یک جہتی اور ان کے نقصانات کے ازالہ کے لیے کیمپوں تک قیام۔ اتنی لچک بڑی غیر معمولی بات تھی۔ دوسری طرف پولیس کی انسدادی کارروائیوں سے مسلمانوں میں خوف و ہراس دور دور تک سرایت کر گیا۔ ان ایام میں تحریک کا مرکز بننے والی مسجد قبا میں نمازیوں کی تعداد برائے نام رہ گئی۔ پولیس والے وردی اور وردی کے بغیر رسم نماز ادا کرتے رہے۔ تیسرے روز صورت حال کا اندازہ کرنے فجر کی نماز کے لیے میں مسجد میں پہنچا۔ یہ مسجد کھوکھر کی کے بڑے قبرستان کے قریب عابد کالونی کی آخری گلیوں میں واقع ہے۔ مسجد کم وبیش ایک کنال اراضی کے لمبوترے پلاٹ پر تعمیر شدہ ہے۔مسجد کا ہال، برآمدہ، اس کے ساتھ وسیع لان ہے۔ لان کے ایک حصے میں باغیچہ کا منظر پر کشش ہے۔ مساجد کے اعتبار سے یہ ایک غیر معمولی کیفیت ہے۔ گرجوں میں باغیچے کا ماحول اور احاطے کی وسعت تو انگریز دور کی یاد گار کے علاوہ این جی اوز کی عنایات کی مرہون منت ہے، جبکہ ہمارے ہاں مساجد زیادہ تر سوسائٹی کی جانب سے پلاٹوں کی خرید اور تجاوزات کی صورت میں معرض وجود میں آتی ہیں۔ اس طرح پلاٹ مختصر اور ان پر تعمیر کاروباری لوگوں کے عطیات سے ہوتی ہے، کیونکہ اہل ثروت کو دو سجدوں کے لیے بھی محل نما مساجد کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ ائمہ و خطبا حضرات کو مسجد محل پر ظل الٰہی جیسا کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ کھوکھر کی کے مضافات میں واقع مسجد قبا عرفان شاہ صاحب کی ذاتی طور پر تعمیر کردہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ مسجد بریلوی مسلک سے منسلک ہے۔
جمعہ کو احتجاج کا پروگرام تھا، چنانچہ جمعہ کی نماز مذکورہ مسجد میں ادا کی۔ دوپہر سوا تین بجے مسجد پہنچا تو عرفان شاہ صاحب کا خطاب جمعہ جاری تھا۔ مجھے برآمدے میں جگہ ملی۔ اپنی چھڑی اور دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر شاہ صاحب کی مہارت خطاب کا مشاہدہ کرنے لگا۔ لوگوں کے جذبات کو بر انگیختہ کرنے میں ان کا ایک ایک جملہ گہرا اثر رکھتا تھا۔ پولیس کی نفری بھی خوب تھی۔ شروع شروع میں احتجاجی ریلی پولیس کی نفری کے مقابلے پر کافی کم تھی، مگر تھوڑی دیر بعد دیگر مساجد سے لوگوں کی بڑی تعداد کی آمد سے خاصی بڑی ریلی منظم ہو گئی۔ میں ریلی میں شامل ہو کر سیالکوٹ روڈ تک ساتھ رہا اور پھر اس خیال سے واپس آ گیا کہ سائیکل لے کر آخر تک ساتھ چلوں گا۔ گھر پہنچ کر مہمانوں کی آمد کے انتظامات نے گھر سے دوبارہ نکلنے کا موقع نہ دیا، البتہ فون پرصورت حال سے با خبر رہا۔ ریلی بخیر و خوبی ریل بازار چوک پر جلسہ کی صورت میں پر امن طور پر ختم ہوئی۔
اختصار سے پیش آنے والے واقعات کے بعد بعض توجہ طلب پہلوؤں کا ذکر لازم ہے۔
سب سے اہم تر بات یہ ہے کہ احتجاج کی قیادت سید عرفان شاہ صاحب خطیب جامع مسجد قبا کے ہاتھ میں رہی۔ ان کی مسجد علاقائی وجہ سے احتجاج کا مرکز بنی۔ اس طرح شاہ صاحب پر قیادت کی ذمہ داری حالات نے ڈال دی۔ شاہ صاحب نے قیادت خوب نبھائی۔ انہوں نے راز داری سے بھی کام لیا اور کسی دوسرے کو قیادت میں شرکت سے بھی دور رکھنے کا پورا اہتمام کیا۔ اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن احتجاج کے برآمد ہونے والے نتائج کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہو گی۔ حالات کے کنٹرول سے باہر ہونے کے بعد جو صورت حال پیدا ہوئی، اس میں شاہ صاحب کو جتنی بھی رعایت دی جائے، اسے ناکامی کے سوا کچھ اور نہیں کہا جاسکتا۔ کیس کی تفتیش اور احتجاج میں تشدد شامل ہونے کے نتیجہ میں وسیع گرفتاریاں، مسلمانوں میں پیدا خوف و ہراس کا ہر پہلو نا خوشگوار ہے اور اس کی ذمہ داری احتجاج کے قائد پر ہی عائد ہو گی۔ احتجاج کو قابو میں نہ رکھنے کے کتنے بھیانک نتائج نکلیں گے، اس کا اندازہ ابھی احتجاج کرنے والوں میں سے کسی کو نہیں۔ اس صورت حال میں لوگوں کا بڑی تعداد میں گرفتار ہونا اور قائدین کا بچ رہنا شعوری ہو یا انتظامیہ کی حکمت عملی کے تحت ہو، نہایت افسوس ناک ہے۔ جماعت کی مقامی قیادت میں سے حکیم کلیم ابتدائی رپورٹ میں نامزد ملزم ہیں۔ انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانت کرائی ہے اور نہ ہی وہ گرفتار ہوئے۔ یہ صورت حال انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کی نشاندہی کرتی ہے۔ عام لوگوں کو قید و بند کا شکار کر کے خود محفوظ رہنے کی حکمت عملی کسی طرح درست نہیں ہو سکتی۔ تحریک کو پر امن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری قائدین کی ہوتی ہے۔ اس کا تشدد کی راہ پر جانا اس کی سو فی صد ناکامی ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مانے یا نہ مانے، احتجاج کی کامیابی اس کے پر امن رہنے میں ہے۔ تشدد کی راہ پر جانے میں دشمن یا انتظامیہ کی سازش کا عنصر بھی ہو سکتا ہے۔ مگر تمام تر نتائج تحریک کے قائدین پر عائد ہوں گے۔
ضرورت اس بات کی تھی کہ احتجاج کو پر امن رکھنے کے لیے بھر پور حکمت عملی اختیار کی جاتی۔ اس میں احتجاج کی نوعیت کا تبدیل کرنا بھی ایک اچھی اور موثر تدبیر ہوسکتی ہے۔ لگتا ہے کہ سید عرفان شاہ اور دیگر قائدین قیادت کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اپنی نا تجربہ کاری کی مار کھا گئے۔ احتجاج کا اگر حاصل یہ ہے کہ خوف و ہراس کے نتیجہ میں تحریک کا مرکز بننے والی مسجد میں نماز یں ادا کرنے کے لیے پولیس کی نفری ہی باقی رہ جائے تو بڑی مایوسی کی بات ہے۔ نعرے اتنے بلند بانگ، ہزاروں کے جلوسوں میں ’’حرمت رسول پر جان بھی قربان‘‘ اور جب آزمائش کا وقت آئے تو لیڈر گرفتاری سے بچ رہیں! مسجدوں میں ادائیگی نماز کے لیے بھی لوگ نہ آسکیں!
پولیس انتظامیہ کے ساتھ معاملات پر مذاکرات میں پبلک کی جانب سے کوئی شخص یا تنظیم کبھی آسان وکٹ پر نہیں ہوتی۔ علما کے لیے تو مذاکرات ہمیشہ ہی دلدل بن جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تفتیش اور پولیس کے اقدامات دونوں میں علما قانون، ضابطہ اور پولیس و انتظامیہ کے مزاج پر گرفت رکھنے کی صلاحیت و مزاج سے محروم ہیں۔ وہ اپنی اعانت کے لیے وکلا کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں مگر اس کی کسی مرحلے میں ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو تحریک کو تشدد کی راہ پر جانے کے بعد مذاکرات میں کچھ حاصل کر لینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے خطرناک مرحلے میں اخلاقی طور پر لوگوں کے ساتھ، آزمائش کے مرحلے میں، بہادرانہ گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مصلحت، بزدلی یا سمجھوتے کے تحت گرفتاری سے بچنا سخت ہزیمت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گرفتار لوگوں کی ضمانتوں کے مرحلے میں، لوگوں کی مدد سے کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا۔ قیادت کے لیے لازم ہے کہ وہ بہادر ہو، حالات پر قابو رکھے، بے قابو ہونے کی انہونی صورت پیدا ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ مرے اور جیے۔ دوستوں کے ہاں پناہ گیری اختیار کرے اور نہ انتظامیہ کے ساتھ سودا بازی سے گرفتاری سے بچنے کی راہ تلاش کرے۔
تازہ صورت یہ ہے کہ اوراق مقدسہ اور رسول اقدس کی اہانت کے دونوں مقدمات کی تفتیش کے بارے میں صورت حال واضح نہیں۔ مقدمات کی ابتدائی رپورٹ نمبر ۱۷۱، ۱۸۳ کہیں سے مہیا نہیں۔ قانون کی رو سے اس کا ایک پرت علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے۔ وہاں یہ پرت نہیں گیا۔ تھانے سے بھی یہ مہیا نہیں ہوا۔ ایس پی کے دفتر میں بھی یہ دستیاب نہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایف آئی آر ایک پبلک دستاویز ہے۔ قانونی طور پر یہ دستاویز ہر ایک کے لیے کھلی ہے، مگر یہ کہیں بھی مہیا نہیں۔ اس پر علما کیا احتجاج کر سکتے ہیں! وہ قانون کے اس پہلو سے بے خبر رہیں گے۔ واقعات کی تفتیش میں پولیس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کوئی نہیں جانتا۔ پولیس سب کچھ خاموشی اور راز داری سے کر رہی ہے۔ تفتیش صاف اور شفاف ہے یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ تو واضح ہو الزامات کیا ہیں، کس پر ہیں اور کن شواہد کی بنیاد پر ہیں؟ ان شواہد کی جانچ کے لیے، پولیس کس حد تک اپنی ذمہ داری قانون اور انصاف کی رو سے پورا کر رہی ہے؟ اس بارے میں علما کچھ کہنے کو تیار ہیں اور نہ ہی پولیس حکام کچھ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر، ایف آئی آر سیل کر دی گئی۔ تفتیش راز داری سے کی گئی تاکہ اشتعال نہ پھیلے۔ یہ سب کچھ غلط اور قانون اور ضابطے کے سخت خلاف ہے۔ ابتدائی رپورٹ کو سیل کر کے اسے پبلک دستاویز کے status سے ایک خفیہ دستاویز تک لے آنے کو کم سے کم بد معاشی کے الفاظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ قانون میں زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی، اس دستاویز کی مدد سے نقص امن کی صورت کو خطرے میں ڈالے تو قانون تحفظ امن عامہ کی دفعہ ۳ کے تحت انسدادی کارروائی کے طور پر اس کے خلاف نظر بندی کا اقدام ہو سکتا ہے یا اگر کوئی نقص امن کا باعث بنے تو مذکورہ قانون کی دفعہ ۱۶کے تحت مقدمہ درجہ کر کے گرفتاری عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ میرے علم کے مطابق قانون میں کسی مقدمے کی رپورٹ ابتدائی کو سیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ سیاسی اور تحریکی کارکنوں کو یہ امر بخوبی سمجھنا چاہیے۔ اس پہلو سے پولیس حکام نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور سخت زیادتی کی ہے۔ تفتیش گم اور خفیہ انداز میں جاری رہی۔ آج تک تفتیش کے بارے میں کوئی اعلان تفتیش کرنے والوں کی جانب سے جاری نہیں ہوا۔ اس سے لوگوں میں بجا طور پر بے چینی اور بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔
سارے قضیے میں مقامی، صوبائی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر این جی اوز نے عیسائی کمیونٹی کی بھر پور ر اخلاقی امداد کی ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ مسلمانوں کا کیس پرنٹ اور اسکرین میڈیا سے غائب کر دیا گی۔ ابتدائی رپورٹ خفیہ کر دی گئی۔ تفتیش کے مراحل اور نتائج بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اگر عیسائی کمیونٹی اکثریتی احتجاج سے خوف و ہراس کا شکار ہوئی تو مسلمان اکثریت میں ہوتے ہوئے میڈیا، انتظامیہ اور علما کی بے تدبیری سے خود کتنے دباؤ کا شکار ہوئے! اس کیس کو عیسائیوں کی جانب سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر لیا جا رہا ہے۔ ۸۲ این جی اوز مسیحی برادری کی حمایت میں ہیں۔ ان میں اکثر این جی اوز مسلمانوں کی ہیں۔ انٹر نیٹ پر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ صورت حال مقامی انتظامیہ پر دباؤ کا باعث ہے۔ میڈیا خاموش ہے یا خاموشی کا پابند کر دیا گیا ہے۔ واقعہ سنگین ہونے اور احتجاج میں پوری توانائی کے باوجود، اسے مقامی سطح تک کارنر کر کے مکمل طور پر کچل دیا گیا بلکہ تفتیش میں بھی جانب داری اور بد دیانتی کے کھلے شواہد سامنے آچکے ہیں، لیکن احتجاجی تحریک کی پسپائی سی پسپائی ہے کہ کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ تحریک کے تشدد کی راہ پر جانے سے تحریک اخلاقی ہمدردی اور حمایت کھو بیٹھی۔ یہ پہلو قیادت کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔
امن وامان کی صورت کو کنٹرول کرنے کے لیے اندھا دھند گرفتاریاں بڑی زیادتی تھی۔ نابالغ بچوں تک کو گرفتاری اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لطف یہ ہے کہ امن کے قیام کی منزل سر کر لینے کے بعد بعد بھی گرفتاریوں کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ اس بارے میں ابتدائی رپورٹ نمبر ۱۸۴ تھانہ جناح روڈ اور ابتدائی رپورٹ نمبر ۵۲۱ تھانہ سول لائن میں درج ہوئیں۔ دونوں رپورٹس علیحدہ تھانوں میں درج ہوئی ہیں۔ ان کے مرتب کرنے والے بھی مختلف ہیں، لیکن مضمون میں اتنی یکسانیت پائی جاتی ہے کہ مصنف ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ دونوں میں بعض جملے بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ نفرت اور اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں اور نعرے لگائے گئے۔ یہ الزام مبہم ہی نہیں، بے معنی ہیں۔ نفرت اور اشتعال پیدا کرنے والی تقریروں کے جملے اور نعرے اور متعلقہ اشخاص کا رپورٹ میں واضح طور پر درج کیا جانا ضروری تھا۔ اسی طرح دونوں رپورٹس میں کہا گیا کہ دو اڑھائی سو افراد امن عامہ کو برباد کر رہے تھے۔ رپورٹ مرتب کرنے والے پولیس افسر ان ان دو اڑھائی سو افراد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو سامنے آنے پر وہ شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ جملے بھی لا یعنی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اگر ان کی پہچان اتنی ہی غیر معمولی اور طاقتور ہے تو ایسے افراد کے حلیے، قد کاٹھ، رنگ روپ اور لباس و چال ڈھال کا ذکر متعین انداز میں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بغیر ایسے جملے کی آڑ میں گرفتاری کے لیے ایک ایسا کھلا لائسنس حاصل کرنے والی بات ہے جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔
ان مقدمات میں، انسداد دہشت ایکٹ کی دفعہ لگایا جانا سخت ظلم ہے۔ یہ واقعہ سخت اشتعال انگیز صورت حال میں بہت معمولی فساد کا ہے جسے آنسو گیس اور گرفتاریوں سے کنٹرول بھی کر لیا گیا۔ دہشت گردی کا ٹھپہ لگا کر انتظامیہ نے صورت حال کو بگاڑا ہے۔ اوراق مقدسہ اور رسول اقدس کی توہین پر احتجاج کے ذرا سے بے قابو ہو جانے پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر پولیس انتظامیہ نے سخت بے تدبیری سے کام لیا ہے۔ اس سے این جی اوز کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اسے حسن تدبیر کہنا ممکن نہیں ہو گا۔ حقیقت میں یہ انتظامیہ کی جانب سے دہشت گردی کے مترادف ہے۔ دہشت گردی کی دفعات کو انتظامیہ امرت دھارا نہ سمجھے۔ یہ دفعات بہت ہی غیر معمولی صورت حال کے لیے ہیں۔
اس معاملے میں پولیس انتہائی بد دیانتی کی حدوں کو بھی پار کر گئی ہے۔ یہ پہلو سخت قابل مذمت ہے ۔ ہوا یہ کہ پولیس نے تھانہ سول لائن میں اس تصادم کے بارے میں ابتدائی رپورٹ نمبر ۵۲۱ مورخہ ۳۰؍اپریل کو درج کی۔ اس رپورٹ میں مقدمہ کے لیے جو دفعات لگائی گئیں، وہ 427/295,431/147,149/353,186 تعزیرات پاکستان ہیں۔ ایف آئی آر کے خانہ نمبر ۳ اور اس کے متن میں یہی دفعات درج ہیں۔ عدالت میں موصولہ رپورٹ مقدمے کی حقیقی شکل پر واضح شہادت ہے۔ اس ابتدائی رپورٹ میں بعد میں پولیس حکام نے دفعہ 7-ATA کا اضافہ کیا۔ یہ اضافہ ضابطے کے تحت ممکن تھا۔ ایک ضمنی لکھ کر ایسا آسانی سے کیا جاسکتا تھا، مگر ایف آئی آر کے متن میں کمی بیشی کرنا واضح طور پر جعل سازی ہے۔ پولیس حکام کا پبلک ریکارڈ میں اس طرح کا جعل سازی کرنا سنگین نوعیت رکھتا ہے۔ پھر یہ جعل سازی ایسے کیس میں ہو جس میں پبلک وسیع پیمانے پر فریق ہے، اس صورت حال کا سنجیدہ نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اتفاق سے ہماری بار کے ایک ذمہ دار وکیل جناب شہزاد اشرف کے نوٹس میں یہ جعل سازی آئی تو انہوں نے پوری جرات سے خود سائل بن کر پولیس حکام کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے مقدمہ کے اندراج کے لیے باقاعدہ درخواست ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22-A/22-B کے تحت دائر کی۔ سیشن جج جناب رشید قمر صاحب نے اس درخواست پر ریلیف دینے کے بجائے وقتی طور پر ٹالنے کی راہ اختیار کی اور سائل کو، جو کہ ہماری بار کے ایک جرات مند وکیل ہیں، مشورہ کے انداز میں پیار پوچا ڈال کر درخواست واپس واپس لینے پر آمادہ کر لیا۔ یہاں میرے عزیز بھائی ناتجربہ کاری کی مار کھا گئے۔ سیشن جج صاحب نے پولیس کے ایک سنگین جرم کو عملاً تحفظ فراہم کیا۔ سیشن جج صاحب نے اپنے تجربے، مہارت اور اختیار کو طاقتور فریق کے حق میں استعمال کیا۔ انہوں نے میرے عزیز وکیل صاحب کو خود فریق نہ بننے کے بجائے متاثرہ سائل کو میدان میں لانے کا مشورہ دیا۔ سیشن جج صاحب کا یہ رویہ کسی طرح ان کے منصب کے مطابق نہیں تھا۔ قانون کی رو سے ہر شہری، کسی بھی جرم کے ارتکاب کا علم ہونے پر، اس کی اطلاع دینے کا پابند ہے۔ اس میں وکیل کا کوئی استثنا نہیں۔ وکیل کو تو عام شہری سے زیادہ ذمہ دار خیال کیا جانا چاہیے۔ پولیس کے خلاف وکلا سے بڑھ کر کون میدان میں اتر سکتا ہے؟ پولیس کے خلاف کسی پرائیویٹ شخص کا سائل بننے کی توقع، جج صاحب اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں، مگر زمینی حقائق بہت مختلف ہیں۔ میں مان نہیں سکتا کہ سیشن جج صاحب اس زمینی صورت حال سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ جج صاحب بہت جذباتی شخص معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے شخص سے اس طرح کی فروگذاشت ہر وقت ممکن ہے۔ یہ فروگذاشت طاقت ور پولیس کے حق میں ہو تو جج صاحب کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑے گی۔
مجھے دکھ کے ساتھ واضح کرنا پڑتا ہے کہ وکیل سوسائٹی میں ظلم کے خلاف پروٹیکشن کی علامت ہے۔ کسی آبادی میں ایک وکیل کی رہائش اس آبادی کے لیے تحفظ کے قوی احساس کا باعث ہے۔ وکلا تحریک کے دوران اعتزاز احسن کہا کرتے تھے کہ ’’پندرہ کروڑ عوام میرے کلائنٹ ہیں‘‘۔ اسی طرح اگر وکیل پیسے ٹھگنے والی مشین نہیں تو وہ یقیناًہر ظلم کے خلاف موثر جد و جہد کی مضبوط علامت ہے۔ جناب شہزاد اشرف ایڈووکیٹ ایسی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں ان کی اس کاوش پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان شا ء اللہ وہ دن دور نہیں جب وکلا میں سے راست رو لوگ، سوسائٹی کے استحصال کے بجائے استحصالی قوتوں کے لیے ضرب کلیمی بن کر ابھریں گے۔
توہین رسالت کے مرتکب کے لیے توبہ کی گنجائش
مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی
(توہین رسالت پر قتل کی سزا کی فقہی حیثیت کیا ہے اور کیا مجرم کے لیے کسی درجے میں توبہ کی گنجائش ہے؟ اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی مدظلہ العالی کا موقف ’الشریعہ‘ کے ایک گزشتہ شمارے میں پیش کیا جا چکا ہے۔ جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور کے ترجمان ماہنامہ ’’الحامد‘‘ نے مارچ ۲۰۱۱ء کے شمارے میں اسی سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم (صدر دار العلوم کراچی) کا مضمون شائع کیا ہے جو ’’الحامد‘‘ کے شکریے کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مدیر)
توہین رسالت کے سلسلے میں مسلمان کا حکم
یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور توہین رسالت کا مرتکب ہو جائے تو اس سے وہ کافر اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جرم ثابت ہونے پر اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کی یہ سزا حکومت وقت دے گی، عوام کو اس کا اختیار حاصل نہیں۔ یہ شق اجماعی ہے اور اس کے دلائل نہایت واضح ہیں اور خود یہ عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی ایسے بدبختوں کو موت کی سزا دی ہے جن کے قصے کتب حدیث اور سیرت میں مشہور ہیں۔
۱۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد (الصارم المسلول، ص ۹۲)
۲۔ فی اکفار الملحدین للعلامۃ الکاشمیری رحمہ اللہ تعالی: فی کتاب الخراج: اجمع المسلمون علی ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر ’’شفا‘‘ (ص ۵۴)
اور اس کا یہ کفر ’’ارتداد‘‘ کے حکم میں ہوگا۔
۳۔ فی رسائل ابن عابدین: الساب المسلم مرتد قطعا الخ (ص ۳۱۹)
۴۔ وفیہا: من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ابغضہ کان ذلک منہ ردۃ الخ (ص ۳۲۵)
۵۔ وفی الدرالمختار : حکمہ حکم المرتد الخ ( ۴/۲۳۴)
۶۔ وفی فتح الباری: ومن طریق الولید بن مسلم عن الاوزاعی ومالک فی المسلم ھی ردۃ الخ وغیر ذلک من الکتب الفقہیۃ۔
اور مرتد اگر مرد ہو اور وہ سچی توبہ نہ کرے تو اس کی سزا بھی بحکم نصوص قطعی قتل ہی ہے۔ اس سے بھی معلو م ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔
اس سلسلہ میں ذمی کا حکم
توہین رسالت کا مذکورہ حکم مسلمان کے بارے میں اجماعی ہے، البتہ ذمی کے بارے میں معمولی سا اختلاف ہے اور توہین رسالت کا مسئلہ زیادہ تر چونکہ غیر مسلموں کی طرف سے پیش آتا ہے، اس لیے اس کا خلاصہ ’’الصارم المسلول‘‘ سے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:
(۱) امام مالک،اہل مدینہ، امام احمد بن حنبل، فقہاء حدیث، خود امام شافعیؒ کے نزدیک ذمی کو بھی مسلمان کی طرح توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔
(۲) امام شافعیؒ کے اصحاب کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ جہاں تک امام ابوحنیفہ اوران کے اصحاب کا مذہب ہے تووہ درج ذیل عبارات سے واضح ہے او ر وہ یہ کہ توہین رسالت کا مرتکب اگر ذمی ہے تو پہلی دفعہ میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ امام اس پر مناسب تعزیر جاری کرے گا۔ البتہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب مکرر کرے تو اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ عربی عبارات درج ذیل ہیں:
۷۔ وتحریر القول فیہ ان الساب ان کا ن مسلما فانہ یکفر ویقتل بغیر خلاف وھو مذہب الائمۃ الاربعۃ وغیرہم وقد تقدم ممن حکی الاجماع علی ذلک اسحاق بن راہویہ وغیرہ، وان کان ذمیا فانہ یقتل ایضاً فی مذہب مالک واھل المدینۃ وسیاتی حکایۃ الفاظہم، وھو مذہب احمد وفقہاء الحدیث، واما الشافعی فالمنصوص عنہ نفسہ ان عہدہ ینتقض بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ یقتل ہکذا حکاہ ابن المنذر والخطابی وغیرہما۔
واما ابوحنیفۃ واصحابہ فقالوا: لا ینتقض العہد بالسب ولا یقتل الذمی بذلک لکن یعزر علی اظہارہ ذلک کما یعزر علی اظہار المنکرات التی لیس لہم فعلہا من اظہار اصواتہم بکتابہم ونحو ذلک وحکاہ الطحاوی عن الثوری ومن اصولہم ان مالا قتل فیہ عندہم مثل القتل بالمثقل والجماع فی غیر القبل اذا تکرر فللام ان یقتل ...... لہذا افتی کثرہم بقتل من اکثر من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الذمۃ وان اسلم بعد اخذہ، وقالوا: یقتل سیاسۃ الخ (ص۳ تا ۱۱)
مسلمان مرتکب توہین کی توبہ کا حکم
اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب شخص کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں او راس توبہ سے اس کے قتل کی سزا معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر قابل قبول ہے تو کب؟ اور توبہ کی نوعیت کیا ہو گی؟ اس کو ’’استتبابہ‘‘ کہتے ہیں۔
اس میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ اس شخص کا قتل ’’حداً‘‘ ہے یا ’’ردۃ‘‘ ہے، چنانچہ جو حضرات کہتے ہیں اس کا قتل ردۃً ہے، وہ استتابہ کے قائل ہیں او رجو حضرات کہتے ہیں کہ اس کا قتل حداً ہے، ان کے نزدیک اس میں عفو کی کوئی صورت نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص سچی توبہ کرے تو توبہ کرنے سے اس کا آخرت کا معاملہ سدھر جائے گا، البتہ دنیا میں اس کی سزائے قتل ساقط نہیں ہوگی، خواہ گرفتاری سے قبل ہو یا گرفتاری کے بعد ہو، کیوں کہ حد ثابت ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کو معاف کر سکتا ہے، چنانچہ حضرت ا بن مسعودؓ سے یہی مروی ہے:
۸۔ لا ینبغی لوال ان یوتی بحد الا اقامہ (مصنف عبدالرزاق وغیرہ :۷/۳۷۰)
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی صراحۃً منقول ہے:
۹۔ لا عفو فی الحدود عن شئ منہابعد ان تبلغ الامام
۱۰۔ فی اکفار الملحدین : فی قبول التوبۃ فی احکام الدنیا اختلاف وتقبل فیما بینہ وبین اللہ تعالیٰ الخ (ص ۵۴)
۱۱۔ فی رسائل ابن عابدین: وممن قال ذلک مالک بن انس واللیث واحمد واسحاق وھو مقتضی قول ابی بکر رضی اللہ عنہ ولا تقبل توبتہ عند ھولاء وبمثلہ قال ابوحنیفۃ واصحابہ والثوری واھل الکوفۃ والاوزاعی فی المسلم لکنہم قالوا: ھی ردۃ الخ
۱۲۔ وفیہا : وقال فی محل آخر قال ابوحنیفۃ واصحابہ: من برئ من محمد اوکذب بہ فھو مرتد حلال الدم الا ان یرجع الخ
۱۳۔ وفیہا : وبعد فاعلم ان مشہور مذہب مالک واصحابہ وقول السلف وجمہور العلماء قتلہ حداً لا کفراً ان اظہر التوبۃ منہ، ولہذا لا تقبل توبتہ ولا تنفعہ استقالتہ وحکمہ حکم الزندیق، سواء کانت توبتہ بعد القدرۃ علیہ والشہادۃ علی قولہ او جاء تائباً من قبل نفسہ لانہ حد وجب لاتسقطہ التوبۃ کسائر الحدود، قال القابسی: اذا اقر بالسب وتاب منہ واظہر التوبۃ قتل بالسب لانہ ھو حد، وقال محمد بن ابی زید مثلہ واما مابینہ وبین اللہ تعالیٰ فتوبتہ تنفعہ ، وقال ابن سحنون: من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموحدین ثم تاب لم تزل توبتہ عنہ القتل۔
۱۴۔ وفیہا بعد التفصیل الطویل: اقول: فقد تحرر من ذلک بشہادۃ ھولاء العدول الثقات الموتمین ان مذہب ابی حنیفۃ قبول التوبۃ کمذہب الشافعی، وفی الصارم المسلول لشیخ الاسلام ابن تیمیہ قال: وکذلک ذکر جماعۃ آخرون من اصحابنا انہ یقتل ساب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقبل توبتہ سواء کان مسلما او کافرا وعامۃ ھولاء لما ذکروا المسئلۃ قالوا: خلافاً لابی حنیفۃ والشافعی، وقولہما ای ابی حنیفۃ والشافعی: ان کان مسلماً یستتاب، فان تاب والاقتل کالمرتد وان کان ذمیا ..... الخ
۱۵۔ وفیہا: وقال ابویوسفؒ وایما رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالیٰ وبانت منہ امراتہ فان تاب والا قتل وکذلک المراۃ الا ان اباحنیفۃ قال: لا تقتل المراۃ علی الاسلام انتہیٰ بلفظہ وحروفہ الخ (ماخوذۃ من رسالۃ تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام المتضمنۃ لرسائل ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ)
۱۶۔ وفی الشرح الصغیر للددیر: (وقتل الزندیق) بعد الاطلاع علیہ بلااستتابۃ وھو من اسر الکفر واظہر الاسلام وکان یسمٰی فی زمن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقاً (بلا قبول توبۃ) من حیث قتلہ، ولا بدمنہ من توبتہ لکن ان تاب قتل حداً والا کفراً ( الا ا ن یجء) قبل الاطلاع علیہ فلا یقتل ....کالساب للنبی مجمع علیہ فیقتل بدون استتابۃ ولاتقبل توبتہ ثم ان تاب قتل حداً ولا یعذر بجھل لانہ لایعذر احدفی الکفربالجہل (اوالسکر) حراما (او تہور) کثرۃ الکلام بدون ضبط ولا یقبل منہ سبق اللسان او غیظ (او بقولہ: اردت کذا) الخ ( ۴/ ۴۳۸)
وفی استتابۃ المسلم خلاف، ہل یستتاب فان تاب ترک والا قتل او یقتل لو تاب والراجح الاول۔
وفی حاشیۃ علی الشرح الصغیر للصاوی: (قولہ: والراجح الاول) ای قبول التوبۃ کما ھو مذہب الشافعی الخ ( ۴/۴۴۰)
ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے او را س کا حاصل یہ ہے کہ شافعیہ اور حنفیہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے اور اس کی وجہ سے اس سے قتل کی سزا ساقط ہو جائے گی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کے نزدیک اس کی توبہ دنیا کے حق میں قبول نہیں ہو گی اور توبہ کی وجہ سے اس کی سزا قتل ساقط نہیں ہوگی۔
امام مالک اور ان کے اصحاب کا مذہب مشہور یہی نقل کیا گیا ہے جیسا کہ عبارت نمبر ۱۳ سے واضح ہے، لیکن مالکیہ کی مشہور کتاب الشرح الصغیر اوراس کے حاشیہ میں ترجیح قبول توبہ کو دی جائے گی۔ ملاحظہ ہو : عبارت نمبر ۱۶۔
البتہ بزازیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کے ہاں بھی اس کو حد کے طورپر قتل کیا جائے گا اور بزازیہ کی اتباع میں متاخرین حنفیہ نے بھی اس قول کو ذکر کیا ہے، لیکن علامہ شامیؒ نے اس کی سخت تردید کی ہے اور اس کو غلط فہمی قرار دیا ہے ۔ لہٰذا اس سلسلہ میں اس قول پر اعتماد نہ کیا جائے، چنانچہ ان کی عبارت ملاحظہ ہو:
۱۷۔ فی الشامیۃ بعد بحث طویل یرد علی البزازیۃ: فقد علم ان البزازی قد تساہل غایۃ التساہل فی نقل ہذہ المسالۃ ولیتہ حیث لم ینقلہا عن احد من اہل مذہبنا بل اسند الیٰ مافی الشفاء والصارم امعن النظر فی المراجعۃ حتی یری ماھو صریح فی خلاف ما فہمہ ممن نقل المسالۃ عنہم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، فلقد صار ہذا التساھل سبباً لوقوع عامۃ المتاخرین عنہ فی الخطا حیث اعتمدوا علی نقلہ وقلدوہ فی ذلک ولم ینقل احد منہم المسئلۃ عن کتاب من کتب الحنفیۃ بل المنقول قبل حدوث ھذاالقول من البزازی فی کتبنا وکتب غیرنا خلافہ (۴؍۲۳۴) کذا فی شرح عقو درسم المفتی لابن عابدین (ص۳۲)
ذمی مرتکب توہین کی توبہ کا حکم
اس میں تین اقوال مشہور ہیں:
ا۔ ذمی کو بہرحال قتل کیا جائے گا، اگرچہ گرفتاری کے بعد، توبہ بھی کر لے۔ یہ امام احمد اور امام مالک کا مشہور موقف ہے اور امام شافعیؒ کا ایک قول ہے۔
۲۔ ذمی اگر توبہ کرے اور توبہ کامطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے تواس کی یہ توبہ قبول کی جائے گی ۔ یہ امام احمد اور امام مالک رحمہما اللہ سے ظاہرالروایۃ ہے۔
۳۔ ذمی کو قتل کیا جائے گا مگر یہ کہ یا تو اسلام لے آئے یا حقیقی ذمی بن جائے اور اسی پر امام شافعی کا ظاہر کلام دلالت کرتاہے۔ (خلاصہ ماخوذہ از الصارم المسلول ص۳۳۰)
ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ استتا بہ کے مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور مالکیہ کے راجح قول کے مطابق مسلمان کی توبہ قابل قبول نہیں اور ذمی کی توبہ کے بارے میں مذکورہ بالا تین اقوال ہیں۔ اس لیے زمانہ کے حالات اور تقاضوں کے مطابق حکومت وقت ان دو میں سے کسی بھی موقف کے مطابق قانون بنا سکتی ہے، لیکن شان رسالت اور ناموس رسالت کی انتہائی عظمت اور جلالت شان کا تحفظ بہرحال انتہائی ضروری ہے، اور اگر قانون میں توبہ کی گنجائش نکالی گئی تو توبہ کا وہی طریقہ کا ر اختیار کرنا ہوگا جو اس سنگین ترین جرم کے مطابق ہو جس کا طریقہ ذیل ہے:
توبہ کا طریقہ
(۱) مذکورہ بالا تفصیلات سے واضح ہو چکا ہے کہ توہین رسالت کا مرتکب شخص بالاتفاق دائرۂ اسلام سے خارج ہو چکاہے، لہٰذا توبہ کی صورت میں اس کے لیے سربرآوردہ علما وعوام کے مجمع میں فوراً تجدید ایمان کرنی لازم ہو گی اور اس کا اسی قدر اعلان ہوگا جس قدر ان حرکتوں کا اعلان ہو چکا تھا۔
(۲) چونکہ کافر ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ختم ہو چکا تھا، اس لیے اسلام لاتے ہی فوراً نکاح کی تجدید کرنی لازم ہوگی اوراس کا اعلان بھی اسی طرح ہو گا جس طرح تجدید ایمان کا اعلان کیا تھا۔
(۳) یہ شخص گزشتہ جرم پر انتہائی شرمندہ رہے گا۔
(۴) اس وقت انتہائی عاجزی اور گریہ وزاری سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔
(۵) آئندہ کے لیے ان سب باتوں کے نہ کرنے کا پختہ عہد کرے۔
(۶) توہین رسالت پر مشتمل مواد اگر کتاب اور تحریری شکل میں ہو تو اس صورت میں اس کے سارے موجود نسخے جلائے اور جہاں جہاں یہ کتاب یا رسالہ پہنچا ہے، ہر ممکن طریقہ سے وہاں سے اس کو ختم کرانے کی کوشش کرے۔ اخبارات کے ذریعے اس کا عام اعلان کرے کہ میں اس کتاب یا رسالہ سے براء ت کا مکمل طریقہ سے اعلان کرتا ہوں، لہٰذا اس کتاب کو جلایا جائے یا کم از کم اس سے میرے نام کا ورق جلایا جائے۔
توہین رسالت کی سزا کے متعلق حنفی مسلک
محمد مشتاق احمد
(علامہ ابن عابدین الشامی کی معرکۃ الآرا تحقیق کا خلاصہ)
ماہنامہ ’’الشریعہ ‘‘ کے مارچ ۲۰۱۱ء کے شمارے میں راقم کا ایک مقالہ ’’ توہین رسالت کی سزا فقہ حنفی کی روشنی میں ‘‘ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس مقالے کے آخر میں تمام مباحث کا خلاصہ راقم نے ان سات نکات کی صورت میں پیش کیا تھا :
’’ ۱۔ کسی شخص کو اس وقت تک گستاخ رسول قرار نہیں دیا جاسکتا جب تک مقررہ شرعی ضابطے پر اس کا جرم ثابت نہ ہو۔
۲ ۔ اگر گستاخ رسول اس جرم سے پہلے مسلمان تھا تو اس کے اس جرم پر ارتداد کے احکام کا اطلاق ہوگا اور اگر وہ پہلے ہی غیر مسلم تھا تو پھر اس فعل پر سیاسۃ کے احکام کا اطلاق ہوگا ۔
۳ ۔ حد ارتداد کو ملزم کے اقرار یا دو ایسے مسلمان مردوں کی گواہی ، جن کا کردار بے داغ ہو ، سے ہی ثابت کیا جاسکتا ہے ، جبکہ سیاسۃ کو عورتوں اور غیر مسلموں کی گواہی ، نیز قرائن اور واقعاتی شہادتوں سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے ۔
۴ ۔ پہلی صورت میں سزا بطور حد موت ہے لیکن سزا کے نفاذ سے پہلے عدالت مجرم کو توبہ کے لیے کہے گی اور اگر عدالت اس کی توبہ سے مطمئن ہو تو اس کی سزا ساقط کردے گی ۔ دوسری صورت میں کوئی مقررہ سزا نہیں ہے بلکہ جرم کی شدت و شناعت اور مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت مناسب سزا سنائے گی ، جو بعض حالات میں سزاے موت بھی ہوسکتی ہے ۔ سیاسۃً دی جانے والی سزا کو حکومت معاف کرسکتی ہے اگر مجرم کا طرز عمل تخفیف کا متقاضی ہو ۔
۵ ۔ حد ارتداد حق اللہ ہے اور سیاسۃ کی سزا حق الامام ہے ، اور حنفی فقہا کے مسلمہ اصولوں کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق الامام دونوں سے متعلق سزاؤں کا نفاذ حکومت کا کام ہے ۔
۶ ۔ اگر کسی شخص نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے شخص کو قتل کیا جو پہلے مسلمان تھا لیکن توہین رسالت کے نتیجے میں مرتد ہوگیا تھا اور اس کا جرم مقررہ ضابطے پر ثابت ہوا تھا ، تو قاتل کو قصاص کی سزا نہیں دی جائے گی لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر اس قاتل کو سیاسۃً مناسب سزا دی جاسکے گی ۔ اگر مقتول کا جرم مقررہ ضابطے پر ثابت نہیں ہوا تھا تو سیاسۃ کے علاوہ قاتل کو قصاص کی سزا بھی دی جائے گی ۔
۷ ۔ اگر مقتول پہلے سے ہی غیر مسلم تھا اور اس کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا تھا ، یا اسے عدالت کی جانب سے سزاے موت نہیں سنائی گئی تھی ، یا اس سزا میں تخفیف کی گئی تھی ، تو قاتل کو قصاص کی سزا بھی دی جائے گی اور سیاسۃً کوئی اور مناسب سزا بھی سزا بھی دی جاسکے گی ۔ اگر مقتول کا جرم بھی ثابت تھا اور اسے سزاے موت بھی سنائی گئی تھی تو قاتل کو قصاص کی سزا نہیں دی جائے گی لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر تادیب کے لیے اسے سیاسۃً مناسب سزا دی جاسکے گی ۔ ‘‘
ان نتائج بحث میں سے بعض پر چند اہل علم کی جانب سے عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا کیونکہ ان کی راے میں متاخرین فقہاے احناف کی راے اس مقالے میں نظر انداز کی گئی تھی۔ درحقیقت متاخرین کی اختلافی راے پر راقم نے مقالے کے حواشی میں بحث کی تھی اور شاید اسی وجہ سے بعض اہل علم اسے نظر انداز کرگئے تھے۔ اس مقالے میں راقم کا مفروضہ یہ تھا کہ متاخرین کی راے حنفی مسلک کی صحیح نمائندگی نہیں کرتی ۔ اس موضوع پر اپنی جانب سے مزید کچھ کہنے کے بجاے راقم نے مناسب خیال کیا کہ اس مسئلے میں علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی کی معرکہ آرا تحقیق کا خلاصہ پیش کر دیا جائے۔
توہین رسالت کی سزا کے متعلق معاصر اہل علم کی بحث میں بالعموم قاضی عیاض بن موسی کی الشفا بتعریف حقوق المصطفی اور شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے مندرجات کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے ۔ قاضی عیاض کا تعلق مالکی مسلک سے جبکہ امام ابن تیمیہ کا تعلق حنبلی مسلک سے تھا۔ شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے ممتاز فقیہ خاتمۃ المجتہدین تقی الدین السبکی کی نہایت اہم تالیف السیف المسلول علی من سبّ الرسول کو بالعموم اس سلسلے میں نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم علامہ ابن عابدین الشامی کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ ان کی تحقیق کا جو خلاصہ رد المحتار میں ملتا ہے، اس سے لوگوں نے بالعموم مختلف اقتباسات سیاق و سباق سے کاٹ کر نقل کیے ہیں اور یوں علامہ شامی نے جس بات کی تردید میں اپنی توانائیاں صرف کی اسی بات کو علامہ شامی کے حوالے سے لوگوں نے نقل کیا ہے ! یہی کچھ ان کے اس رسالے کے ساتھ ہوا ہے جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جارہا ہے ۔
علامہ شامی کا یہ رسالہ ان کے مجموعۂ رسائل کی پہلی جلد میں پندرھویں نمبر پر آتا ہے ۔ اس کا پورا عنوان ہے :
’’تنبیہ الولاۃ و الحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابہ الکرام علیہ و علیھم الصلاۃ و السلام ‘‘
راقم کی راے یہ ہے کہ موجودہ دور کے مخصوص تناظر میں اس عنوان میں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے ۔ اب اسے محض تنبیہ الولاۃ و الحکام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا زیادہ مناسب عنوان شاید تنبیہ العلماء والولاۃ والحکام ہو ۔ راقم نے اس انتہائی اہم رسالے کا انگریزی زبان میں ترجمہ مکمل کر لیا ہے اور آج کل اس پر تحقیقی حواشی اور مقدمہ لکھنے کا کام جاری ہے ۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے ۔
واضح رہے کہ اس مقالے میں راقم کا مطمح نظر توہین رسالت کی سزا کے بارے میں حنفی فقہا کے موقف کے دلائل واضح کرنا نہیں ، بلکہ راقم کا مقصود صرف یہ ہے کہ توہین رسالت کی سزا کے مختلف پہلووں پر حنفی فقہا کے موقف کی صحیح تصویر سامنے لائی جائے ، اگرچہ اس کوشش میں ضمناً فقہاے احناف کے دلائل کا خلاصہ بھی سامنے آجائے گا ۔
علامہ شامی کے رسالے کا اجمالی خاکہ
علامہ شامی نے اپنے اس رسالے کو دو ابواب میں تقسیم کیا ہے :
باب اول میں گستاخ رسول کی سزا پر تفصیلی بحث ہے جبکہ باب دوم صحابۂ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا کے بارے میں ہے۔
چونکہ موضوع زیر بحث کا تعلق باب اول سے ہے اس لیے اس باب کے مندرجات کا خاکہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ شامی نے اس باب کو تین فصول میں تقسیم کیا ہے جن میں پہلی دو فصول اس شخص کے متعلق ہیں جو اس فعل کے ارتکاب سے قبل مسلمان تھا :
فصل اول میں علامہ شامی نے ثابت کیا ہے کہ اگر ایسا شخص اس فعل سے توبہ نہ کرے تو اس کی سزا بطور حد موت ہے۔
فصل دوم میں علامہ شامی نے تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ ایسے شخص سے توبہ کے لیے کہنا لازم ہے اور اگر قاضی اس کی توبہ سے مطمئن ہو تو اس شخص کی دنیوی سزا ساقط ہو جائے گی ۔ انھوں نے تفصیل سے اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا مسلک واضح کیا ہے ۔
فصل سوم اس گستاخ رسول کی سزا کے متعلق ہے جو مسلمان ریاست کا باشندہ ہو ۔ علامہ شامی نے ثابت کیا ہے کہ اس شخص کو فساد کے ارتکاب کی وجہ سے قاضی مناسب سزا دے سکتا ہے جو بعض شنیع صورتوں میں سزاے موت بھی ہوسکتی ہے۔
فصل اول : اگر مسلمان اس جرم کا ارتکاب کرے
علامہ شامی نے اس فصل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے :
پہلے حصے میں انھوں نے اس مسئلے میں فقہا کی آرا اور دلائل کا خلاصہ ذکر کیا ہے ، جبکہ دوسرے حصے میں انھوں نے اس بات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے کہ ایسے گستاخ رسول کی سزا کی علت ’’گستاخی‘‘ ہے یا ’’ کفر ‘‘ ؟
ایسا مجرم اگر توبہ نہ کرے تو اس کی سزاے موت پر اجماع ہے ۔
چنانچہ پہلے حصے میں علامہ شامی نے اس بات پر فقہا کا اجماع نقل کیا ہے کہ اگر مسلمان کہلانے والا شخص رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرے اور اس فعل سے توبہ نہ کرے تو اس کی سزا بطور حد موت ہے ۔ انھوں نے اس ضمن میں بعض لوگوں کے شبہے کا جواب بھی دیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ اس فعل کے ارتکاب سے مسلمان تبھی مرتد ہوگا جب وہ اس فعل کو اعتقاداً جائز سمجھے ۔ علامہ شامی نے قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع و قیاس کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اس فعل کا مرتکب مرتد ہوجاتا ہے خواہ وہ اعتقاداً اس کی حلت کا قائل نہ ہو ۔
سزاے موت کی علت : گستاخی یا ارتداد ؟
اس کے بعد دوسرے مسئلے میں علامہ شامی نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ ایسے شخص کو جو سزا دی جاتی ہے وہ خاص اس گستاخی کے سبب سے دی جاتی ہے یا اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ یہ گستاخی ارتداد ہے اور اس وجہ سے اس شخص کو دراصل ارتداد کی سزا دی جاتی ہے ؟
انھوں نے قرار دیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزاے موت کی علت یہ ہے کہ اس فعل کی وجہ سے وہ مرتد ہوجاتا ہے ۔ اگر گستاخی ہی علت ہوتی تو پھر ہر گستاخ کو بطور حد سزاے موت دی جاتی حالانکہ فقہائے احناف سے صراحت کی ہے کہ غیرمسلم گستاخ رسول کو بعض حالات میں سزاے موت دی جاتی ہے تو وہ بطور حد نہیں بلکہ بطور سیاسۃ دی جاتی ہے۔ چنانچہ پہلے وہ مرتد اور عام کافر میں چند فروق ذکر کرتے ہیں ۔ مثال کے طور عام کافر کو ذمی بناکر اس پر جزیہ عائد کیا جاسکتا ہے اور اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ، جبکہ مرتد کو ذمی نہیں بنایا جاسکتا اور اگر اس نے اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا تو اسے قتل کیا جائے گا ۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قتل مرتد کی علت کفر نہیں بلکہ کفر کی خاص شکل ۔ مسلمان کی طرف سے ارتداد۔ ہے اور ارتداد کی یہ سزا بطور حق اللہ واجب ہے ۔ لہٰذا مرتد کی سزاے موت حد ہے ، خواہ متقدمین فقہائے احناف نے کتاب الحدود میں اس کا ذکر نہ کیا ہو ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ متقدمین بھی ارتداد کے لئے ان ساری صفات کے قائل ہیں جو حد کی ہیں ۔
یہاں ابن عابدین ایک شبہے کا ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر یہ سزا حد ہے تو پھر یہ توبہ سے ساقط کیسے ہوتی ہے ؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مرتد کی بطور حد سزاے موت کی وجہ خاص فعل ارتداد نہیں ہے بلکہ فعل ارتداد کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا سبب اس کا کفر پر قائم رہنے کا ارادہ ہے ۔ اور ایسی علت جو دو اجزا پر مشتمل ہو وہ ان میں کسی کے بھی نہ ہونے کی صورت میں موجود نہیں رہتی ۔ پس اس کے اسلام کی طرف لوٹ آنے کے بعد تنہا ارتداد سزاے موت کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ سزاے موت بیک وقت دو افعال کی جزا تھی ۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ عام قاعدے کے تحت تو بقیہ حدود کی طرح چاہیے تھا کہ یہ حد بھی توبہ سے ساقط نہ ہوتی لیکن کئی آیات و احادیث میں صراحتاً قرار دیا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے پر پچھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں ۔ اس لیے فقہا نے اسے عام قاعدے سے استثنا قرار دیا ہے ۔ اسی طرح اس سزا پر یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے کہ اگر یہ حد ہے تو پھر مرتد عورت پر کیوں نہیں نافذ کی جاتی کیونکہ کئی روایات میں صراحتاً کافر عورتوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے ۔ اس لیے یہ ممانعت بھی ایک استثنائی حکم ہے ۔
فصل دوم : مسلمان کہلانے والے گستاخ رسول کی توبہ کے بعد سزا کا سقوط
اس فصل کو علامہ شامی نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے :
حصۂ اول میں انھوں نے ایسے گستاخ رسول کی توبہ کی قبولیت پر مختلف مسالک کے فقہا کا اختلاف نقل کیا ہے ؛
حصۂ دوم میں انھوں نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا ایسے گستاخ رسول سے توبہ کے لیے کہناواجب ہے؟
حصۂ سوم میں انھوں نے اس مسئلے میں حنفی مسلک کے نمائندہ موقف کی تنقیح کی ہے اور نہایت تفصیل سے امام ابوحنیفہ کی راے کی وضاحت کی ہے ، نیز بعض متاخرین حنفی فقہا کی اختلافی آرا کی کمزوری بھی واضح کی ہے ۔
ایسے مجرم کی توبہ کی قبولیت کے متعلق مذاہب فقہ کا اختلاف
حصۂ اول میں علامہ شامی نے واضح کیا ہے کہ ایسے گستاخ رسول کی توبہ کی قبولیت کے مسئلے پر فقہا کا اختلاف ہے ۔
چنانچہ انھوں نے قاضی عیاض کی الشفا اور دیگر فقہا کی کتب سے طویل اقتباسات نقل کرکے دکھایا ہے کہ فقہا کے ہاں اس مسئلے پر تین آرا پائی جاتی ہیں:
۱ ۔ امام مالک کی مشہور راے یہ ہے کہ ایسے گستاخ رسول کو سزا گستاخی کی ملتی ہے ، نہ کہ کفر کی ، اور اس وجہ سے یہ سزا توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ یہ راے امام شافعی ، امام احمد اور امام لیث سے بھی نقل کی گئی ہے۔
۲ ۔ امام مالک سے ہی دوسری راے کی روایت ولید بن مسلم نے کی ہے اس شخص پر ارتداد کے احکام کا اطلاق ہوگا جن میں ایک حکم توبہ کی قبولیت کا ہے ۔ یہی راے امام ابو حنیفہ ، امام ثوری اور امام اوزاعی کی ہے ۔
۳ ۔ تیسری راے ، جس کی روایت سحنون نے کئی مالکی فقہا سے کی ہے ، یہ ہے کہ اس شخص پر زندیق کے احکام کا اطلاق ہوگا ، گویا اس کی توبہ دنیوی سزا ساقط نہیں کرسکے گی ۔
کیا ایسے مجرم کو توبہ کے لیے کہنا واجب ہے ؟
حصۂ دوم میں علامہ شامی نے واضح کیا ہے کہ جو فقہا ایسے گستاخ کی توبہ کی قبولیت کے قائل نہیں ہیں وہ اس سے توبہ کرانے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ البتہ توبہ کی قبولیت کے قائل فقہا میں بھی اکثریت کا کہنا یہ ہے ، اور یہی حنفی فقہا کا نمائندہ موقف ہے ، کہ اگر ایسے شخص کو توبہ کے لیے کہے بغیر بھی اسے سزاے موت دی گئی تو اس سزا کو جائز سمجھا جائے گا ، اگرچہ قانوناً صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے توبہ کے لیے کہا جائے ، اس کے شبہات دور کیے جائیں اور اسے رجوع کا موقع دیا جائے ۔ علامہ شامی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر ایسا شخص غور و فکر کے لیے مہلت چاہے تو پھر حنفی فقہا کا موقف یہ ہے کہ اسے سوچنے سمجھنے کے لیے مہلت دینا واجب ہے ۔
ایسے مجرم کی توبہ کے قانونی اثرات کے متعلق امام ابو حنیفہ کے مسلک کی تحقیق
حصۂ سوم اس ساری بحث کی جان ہے ۔ یہاں علامہ شامی نے فقہ حنفی کے تمام ذخیرے کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد جو نتائج نکالے ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں ۔ علامہ شامی کی اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ کسی بھی فقہی مسلک ، اور بالخصوص حنفی مسلک ، میں اگر ایک سے زائد آرا پائی جاتی ہوں تو ان میں کسی راے کو اس مسلک کا نمائندہ موقف ماننے کے لیے کیا طریق کار اختیار کرنا چاہیے ۔ اصول قانون اور اصول فقہ پر کام کرنے والوں کے اس فصل میں بہت مفید مواد موجود ہے ۔
امام ابو حنیفہ کے مسلک کے متعلق دیگر مذاہب کے ائمہ کی گواہی
اس مقام پر پہلے تو علامہ شامی نے قاضی عیاض اور امام طبری کے اقتباسات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایسے گستاخ کی توبہ کی قبولیت اور توبہ کے ذریعے اس کی سزا کے سقوط کے قائل تھے کیونکہ وہ اس پر مرتد کے احکام کا اطلاق کرتے تھے ۔ اس کے بعد انھوں نے دو اہم نکات کی طرف توجہ دلائی ہے :
۱ ۔ یہ کہ یہی راے امام مالک سے ولید بن مسلم نے روایت کی ہے کہ ایسے گستاخ پر ارتداد کے احکام کا اطلاق ہوگا۔
۲ ۔ دوسری یہ کہ توبہ کی عدم قبولیت کے متعلق امام مالک کی مشہور راے کی بنیاد یہ امر ہے کہ وہ اس سزا کو گستاخ کے مرتد ہوجانے کی حد نہیں بلکہ خاص گستاخی کے فعل کی حد سمجھتے ہیں ، اور یہی راے قاضی عیاض نے امام شافعی ، امام احمد اور امام لیث سے نقل کی ہے ۔
اس آخری نکتے کے متعلق علامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام احمد کی مشہور راے تو یہی ہے جو قاضی عیاض نے نقل کی ہے ۔ تاہم امام شافعی کے مسلک کی تحقیق کے متعلق علامہ شامی کی راے قاضی عیاض سے مختلف ہے ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ راے شافعی فقیہ ابو بکر الفارسی کی راے کے موافق ہے جو قرار دیتے ہیں کہ حد قذف کی طرح یہ سزا بھی توبہ سے ساقط نہیں ہوتی ( کیونکہ شافعی فقہا کے نزدیک حد قذف حق العبد سے متعلق ہے ، نہ کہ حق اللہ سے متعلق ، اور ابو بکر الفارسی کی راے میں گستاخ رسول کی سزا رسول اللہ ﷺ کے حق سے متعلق ہے ) ۔ دیگر مشہور شافعی فقہا میں ابو بکر القفال اور امام الحرمین نے بھی اسی راے کو ترجیح دی ہے لیکن خاتمۃ المحققین تقی الدین السبکی نے صراحت کی ہے کہ امام شافعی کا مشہور مسلک اس کے برعکس توبہ کی قبولیت ہی کا ہے اور اسی مسلک پر قاضیوں نے فیصلے دیے ہیں ۔ امام سبکی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ امام فارسی کے قول کی روایت مختلف الفاظ میں کی گئی ہے ، اور یہ کہ اس کے قول کی سیاق و سباق اسے گستاخی کی ایک خاص نوعیت ، رسول اللہ ﷺ کے خلاف قذف کے ارتکاب ، کے ساتھ خاص کردیتا ہے ۔ امام الحرمین نے بھی امام فارسی کے قول کی روایت قذف کے لفظ کے ساتھ کی ہے ۔ شافعیہ کے مسلک کے متعلق امام سبکی کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ :
۱۔ گستاخی کی عام صورتوں میں مجرم کو توبہ کے لیے کہا جائے گا اور اگر اس نے توبہ کی تو اس کی سزا ساقط ہوجائے گی ؛
۲ ۔ اگر گستاخی قذف کی نوعیت کی ہو اورپھر مجرم توبہ کرے تو پھر شافعیہ کے ہاں تین آرا ہیں : ایک یہ کہ اس کی سزا ساقط ہوجائے گی ؛ دوسری یہ کہ اس کی سزاے موت ساقط ہوجائے گی لیکن اسے سزاے قذف دی جائے گی ؛ اور تیسری راے یہ ہے کہ اسے سزاے موت ہی دی جائے گی ۔
جہاں تک امام ابوحنیفہ کے مسلک کا تعلق ہے تو امام سبکی نے تصریح کی ہے کہ حنفی مسلک توبہ کی قبولیت ہی کا ہے اور اس میں دو رائیں نہیں پائی جاتیں۔ اس کے بعد علامہ شامی نے اس سلسلے میں امام تیمیہ کی گواہی پیش کی ہے ۔ امام ابن تیمیہ نے بھی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک نقل کیا ہے کہ اگر مجرم پہلے مسلمان ہو اور گستاخی کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کی سزا ساقط ہوجائے گی ۔
امام ابو حنیفہ کے مسلک کے متعلق متقدمین فقہاے احناف کی گواہی
اس کے بعد علامہ شامی قرار دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے متعلق اگر حنفی متون خاموش بھی ہوتیں تو امام طبری ، قاضی عیاض ، امام ابن تیمیہ اور امام سبکی جیسے انتہائی ثقہ اور معتبر فقہاء کی گواہی اس سلسلے میں کافی تھی ۔ تاہم حنفی متون اس سلسلے میں خاموش نہیں ہیں بلکہ وہ صراحتاً اس گواہی کی تائید کرتی ہیں ۔ یہاں علامہ شامی امام ابوحنیفہ کے ممتاز شاگرد امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کی کتاب الخراج سے یہ اقتباس نقل کرتے ہیں جو فقہ حنفی کے موقف کے متعلق بالکل صریح ہے :
و قال ابو یوسف : و أیما رجل مسلم سب رسول اللہ ﷺ أو کذبہ أو عابہ أو تنقصہ، فقد کفر باللہ تعالیٰ ، و بانت منہ امرأتہ ۔ فان تاب، و الا قتل ۔ و کذلک المرأۃ ، الا أن أبا حنیفۃ قال : لا تقتل المرأۃ ، و تجبر علی الاسلام ۔
[ابو یوسف کا قول ہے کہ جو مسلمان رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرے ، یا ان کی تکذیب کرے ، یا ان کی عیب جوئی کرے ، یا ان کی شان میں تنقیص کرے ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے کفر کا ارتکاب کیا اور اس کی بیوی بائن ہوگئی ۔ پھر اگر وہ توبہ کرے تو بہتر ورنہ اسے سزاے موت دی جائے گی۔ یہی حکم عورت کا بھی ہے ۔ البتہ ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اسلام کی طرف لوٹ آنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ]
اس اقتباس سے دیگر امور کے علاوہ علامہ شامی یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ حنفی مسلک کے مطابق توبہ کی قبولیت سے مراد سزا کا سقوط ہے کیونکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ : فان تاب، والا قتل۔
علامہ شامی نے شیخ الاسلام السعدی کی تالیف النتف الحسان سے یہ اہم اقتباس بھی اس سلسلے میں نقل کیا ہے :
من سب رسول اللہ ﷺ فانہ مرتد وحکمہ حکم المرتد، یفعل بہ ما یفعل بالمرتد
[جس نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کی تو وہ مرتد ہوا ۔ اس کی قانونی حیثیت وہی ہے جو مرتد کی ہے، اور اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو مرتد کے ساتھ کیا جائے گا ۔ ]
اس کے بعد انھوں نے اس مفہوم کی کئی عبارات فتاوی مؤید زادہ ، شرح الطحاوی ، معین الحکام اور نور العین شرح جامع الفصولین سے نقل کی ہیں جن سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ حنفی مسلک یہی ہے کہ دیگر مرتد ین کی طرح گستاخ رسول کی سزا بھی توبہ کے بعد ساقط ہوجاتی ہے ۔
ایسے مجرم کی قانونی پوزیشن وہی ہے جو مرتد کی ہے
اس کے بعد علامہ شامی نے ایک اور پہلو سے اس مسئلے کو لیا ہے ۔ انھوں نے دکھایا ہے کہ حنفی فقہا ارتداد کا حکم واضح کرتے ہوئے جب ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جن کے کہنے سے سے کوئی مسلمان مرتد ہوسکتا ہے تو ان میں رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کا بھی ذکر کرتے ہیں ۔ مثال کے طور پر انھوں نے فتاوی تاتارخانیہ سے یہ عبارت نقل کی ہے :
من لم یقر ببعض الأنبیاء، أو عاب نبیاً بشیء، أ و لم یرض بسنۃ من سنن سید المرسلین ﷺ فقد کفر۔
[جس نے انبیاء علیہم السلام میں بعض کا انکار کیا، یا کسی نبی کی عیب جوئی کی، یا سید المرسلین ﷺ کی سنن میں کسی سنت کو ناپسند کیا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔]
اس طرح کی کئی عبارات علامہ شامی نے التتمۃ ، المحیط ، الظاھریۃ اور متون معتبرہ جیسے مختصر القدوری ، کنز الدقائق ، المختار ، ملتقی الأبحر ، الھدایۃ اور امام محمد بن الحسن الشیبانی کی الجامع الصغیر سے نقل کی ہیں ۔ اس کے بعد وہ قرار دیتے ہیں کہ جب حنفی فقہا صراحتاً اس کو ارتداد قرار دیتے ہیں اور پھر ارتداد کے قانونی اثرات میں ایک اہم اثر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ مرتد کو توبہ کے لئے کہا جائے گا اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کو ارتداد کی سزا نہیں دی جائے گی ، تو ظاہر ہے کہ یہی حکم گستاخ رسول کا بھی ہے ۔
اس استدلال پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زندیق بھی تو مرتد ہوتا ہے مگر فقہا اس کی توبہ کے قائل نہیں ہیں تو علامہ شامی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زندیق یا جادوگر کو محض ارتداد کی وجہ سے نہیں ، بلکہ فساد فی الارض کی وجہ سے سزاے موت دی جاتی ہے اور گستاخ رسول کو بھی بعض صورتوں میں ارتداد کے بجائے فساد فی الارض کی بنیاد پر سزاے موت دی جاسکتی ہے ، جیسے مثال کے طور غیر مسلم گستاخ رسول کا حکم ہے ، بلکہ فساد فی الارض کی بنیاد پر سیاسۃً سزاے موت تو زندیق، جادوگر، مرتد یا گستاخ رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس مسلمان کو بھی دی جاسکتی ہے جس نے کفر کا ارتکاب نہ کیا ہو ، جیسے مثال کے طور پر باغیوں کو سیاسۃً سزاے موت دی جاسکتی ہے ۔
بعض متاخرین احناف کی اختلافی راے
یہاں سے علامہ شامی اس بات کی طرف رخ کرتے ہیں کہ بعض متاخرین احناف نے کس بنا پر قرار دیا ہے کہ گستاخ رسول مسلمان کو سزاے موت بطور حد دی جائے گی اور اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی ؟ مثال کے طور پر الفتاوی البزازیۃ میں یہی قرار دیا گیا ہے جس کی اتباع الدرر و الغرر میں کی گئی ہے۔ ابن الھمام نے بھی فتح القدیر میں اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا ہے ۔ نیز ابن نجیم نے الأشباہ و النظائر اور البحر الرائق میں کہا ہے کہ فتوی اسی قول پر دینا چاہیے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوگی ۔ اس بات کی اتباع ان کے شاگرد علامہ تمرتاشی نے التنویر میں کی۔ پھر یہی بات علامہ خیر الدین الرملی ، صاحب النھر اور علامہ شرنبلانی نے اور ان کے بعد دیگر کئی متاخرین نے اپنے فتاوی میں کی ہے ۔
اختلاف کا اصولی فیصلہ
اس اختلاف کا اصولی فیصلہ تو علامہ شامی ان اصولوں کے ذریعے کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ روایات میں اختلاف کی صورت میں مفتی بہ قول کی پہچان کس طرح ہوگی ؟ یہاں علامہ شامی نے شیخ امین الدین بن عبدالعال کے فتاوی سے جو اہم اصول بیان کیے ہیں ان میں سے چند کا یہاں ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے :
- اگر امام ابو حنیفہ سے ایک سے زائد آرا مروی ہوں تو اس راے کی اتباع کی جائے گی جو زیادہ قوی ہو ۔ پس اگر صاحبین کی راے امام کی سے مروی آرا میں کسی ایک سے موافق ہو تو اس کے خلاف راے پر فتوی نہیں دیا جائے گا ۔
- اگر امام اور ان کے تلامذہ میں اختلاف ہو تو امام کی راے پر فتوی دیا جائے گا ، بالخصوص جبکہ صاحبین میں کسی ایک کی راے امام کی راے کے موافق ہو ۔
- اگر امام ایک طرف ہوں اور صاحبین دوسری طرف تو اگر یہ اختلاف کسی شرعی دلیل کی تعبیر و تشریح پر مبنی ہو تو امام کی راے پر عمل کیا جائے گا ، اور اگر اختلاف احوال کے تغیر کی بنا پر ہو تو صاحبین کی راے پر فتوی دیا جائے گا ۔
- اگر کسی مسئلے میں امام کی راے نقل نہ کی گئی ہو تو فتوی ابو یوسف کی راے پر دیا جائے گا ؛ وہ بھی نہ ہو تو محمد کی راے پر ، ورنہ زفر کی راے پر اور وہ بھی نہ ہو تو حسن ( بن زیاد ) کی راے پر فتوی دیا جائے گا ۔
- اگر کسی مسئلے پر ان کبار فقہا یا ان کی طرح کے دیگر فقہا کی راے نہ ملے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان کے بعد کے فقہا نے اس مسئلے میں کوئی متفقہ راے دی ہے یا نہیں ؟ اگر دی ہے تو اسی کی اتباع کی جائے گی ۔ اگر ان کا اختلاف ہو تو پھر جمہور فقہاے مذہب کی راے ، بالخصوص ابو حفص ، ابو جعفر ، ابو اللیث اور طحاوی جیسے فقہا کی راے پر فتوی دینا چاہیے ۔
- اگر یہ راستہ بھی میسر نہ ہو تو پھر مفتی پر یہ ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ وہ ان فقہاے کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود اس مسئلے کا شرعی حل تلاش کرے ۔
- واضح رہے کہ وہی مفتی فقہا کی آرا میں اختلاف کی صورت میں کسی راے کا انتخاب کرسکتے ہیں جو کسی مسئلے کا قانونی تجزیہ کرنے اور اس کے لیے قانونی حکم کے استنباط کے لیے مجتہدانہ بصیرت رکھتے ہوں ۔ باقی رہے ہم اور ہمارے معاصرین ، اور ہمارے ان کے اساتذہ اور ان اساتذہ کے اساتذہ ، تو ہماری حیثیت تو صرف مجتہدین کی آرا کے نقل کرنے والوں اور ان کی حکایت کرنے والوں کی ہے ۔
یہاں علامہ شامی نے ثابت کیا ہے کہ حنفی مسلک میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا اور اس کی شہادت متقدمین احناف کی نصوص بھی دیتی ہیں اور دیگر مسالک کے فقہاء کی عبارات بھی ۔ اس لیے امام بزازی کی عبارت ، جہاں پہلی دفعہ حنفی فقہا کے ہاں ایک مختلف راے ملتی ہے ، اصولاً ناقابل قبول ہے ۔
بزازی اور ان کے متبعین کی راے کے اصل مآخذ
اس کے بعد علامہ شامی نے یہ بات بھی قطعی طور پر ثابت کی ہے کہ فتاوی بزازیہ کی عبارت حنفی فقہا کی تصریحات کے بجائے مالکی فقیہ قاضی عیاض کی الشفا اور حنبلی فقیہ امام ابن تیمیہ کی الصارم المسلول سے ماخوذ ہے ۔ نیز علامہ شامی نے یہ بھی دکھایا ہے کہ بزازی سے قاضی عیاض اور امام ابن تیمیہ کی عبارات کے فہم میں غلطی ہوئی ہے ورنہ قاضی عیاض اور امام ابن تیمیہ دونوں نے حنفی موقف کو صحیح طور پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی نے ثابت کیا ہے کہ ابن الھمام کا انحصار بزازیۃ پر تھا اور خود ابن الھمام کے شاگرد رشید علامہ قاسم نے ان کے قول کو اس بنیاد پر رد کیا ہے کہ وہ حنفی مسلک کے خلاف ہے ۔ اسی طرح ابن نجیم پر خود ان کے اہل عصر نے بھی اس سلسلے میں تنقید کی تھی ، بالخصوص جبکہ ابن نجیم نے حوالہ الجوھرۃ کا دیا ہے لیکن وہاں یہ عبارت نہیں پائی جاتی ۔
کیا توبہ کی قبولیت سے مراد اخروی سزا کا سقوط ہے ؟
یہ ثابت کرنے کے بعد کہ حنفی مسلک توبہ کی قبولیت کا ہی ہے ، علامہ شامی اس تاویل کی طرف رخ کرتے ہیں جو بعض لوگوں نے بزازی اور ابن الھمام وغیرہ کے دفاع میں پیش کی ہے ، کہ توبہ کی قبولیت سے مراد اخروی سزا کا سقوط ہے ، نہ کہ دنیوی سزا ۔ علامہ شامی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تاویل پیش کرنے والے اصل محل نزاع کو ہی نظر انداز کرگئے ہیں۔ قاضی عیاض ، امام ابن تیمیہ ، امام سبکی اور اما م ابو یوسف کی جو عبارات نقل کی گئیں ان میں صراحتاً مذکور ہے کہ اصل بحث سزاے موت کے سقوط یا عدم سقوط پر ہے ۔ چنانچہ امام ابو یوسف قرار دیتے ہیں : فان تاب، والا قتل۔
کیا توبہ اس لیے دنیوی سزا ساقط نہیں کرسکتی کہ مجرم فساد کا ارتکاب کرتا ہے ؟
بزازی اور ابن الہمام کے قول کی ایک اور تاویل یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ اس قول کی بنا یہ امر ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محترم شخصیت کی شان میں گستاخی کرکے مجرم فساد فی الارض کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ حنفی مسلک کا مسلمہ اصول ہے کہ فساد فی الارض کی سنگین صورت میں مجرم کو سزاے موت دی جاسکتی ہے ۔ اس تاویل کا جواب علامہ شامی یہ دیتے ہیں کہ ایک تو گستاخ رسول تعزیری نہیں بلکہ اسے ارتداد کی سزا بطور حد دی جاتی ہے اگر وہ توبہ نہ کرے ، دوسرے اگر سزاے موت فساد کی وجہ سے دی جارہی ہے تو یہ حکم مطلق صورت میں صحیح نہیں ہے کیونکہ فساد کی ہر صورت پر موت کی سزا نہیں دی جاسکتی ، بلکہ صرف اسی صورت میں یہ سزا دی جاتی ہے جب مجرم معاشرے میں عمومی انتشار کا باعث بنے اور اس کے فساد کے خاتمے کے لیے سواے سزاے موت کے اور کوئی راستہ نہ ہو ۔ پس اگر مجرم اسے عادت بنالے کہ جب بھی وہ پکڑا جائے وہ توبہ کرکے خود کو بچانے کی کوشش کرے ، یا وہ جرم انتہائی اشتعال انگیز انداز میں یا سرکشی کے ساتھ کرے تب اسے فساد کا مرتکب قرار دے کر سزاے موت دی جاسکتی ہے لیکن ایسا جرم کی ہر صورت میں نہیں ہوسکتا ۔
کیا اس طرح بزازی اور دیگر فقہا کی کتب پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے؟
یہاں علامہ شامی اس اعتراض کا بھی رد کرتے ہیں کہ ان کے اس موقف کی وجہ سے بزازیہ جیسی مستند کتاب ناقابل اعتماد ٹھہرتی ہے ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام بزازی ، محقق ابن الھمام اور دیگر فقہا جنھوں نے اس راے کا اظہار کیا ہے ، ان کا احترام اور ان کے ساتھ عقیدت اپنی جگہ لیکن اللہ کی کتاب کے سوا کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں ہوسکتی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو احسان کیے ہیں ان میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ ہر دور میں اس نے اپنے بعض بندوں سے یہ کام لیا ہے کہ وہ اپنے پیش رووں کی غلطیوں کا احتساب کرکے شرعی احکام کی توضیح اور احقاق حق کا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ پس فقہا نے اپنے پیش رووں کے کام کا تنقیدی جائزہ لے کر اس میں غث و ثمین کی تمییز کا کام ہمیشہ سے جاری رکھا ہے اور اس سلسلے میں اپنے بزرگوں اور اساتذہ سے بھی اختلاف کرتے آئے ہیں ۔ پھر علامہ شامی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ غلطی کسی ایک اہل علم سے ہوجاتی ہے لیکن ان پر اعتماد کی وجہ سے دوسرے اس راے کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں بات پھیل جاتی ہے لیکن جب یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ پہلا قدم ہی غلط اٹھایا گیا تھا تو پھر اس غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ۔ اس کے بعد انھوں نے کئی ایسی مثالیں دی ہیں جن میں بعض بڑے اہل علم سے کسی مسئلے کے صحیح حکم کے تعین میں تسامح ہوا ہو اور بعد کے فقہا نے اس کی تصحیح کی ہو ۔
کیا ایسے مجرم پر مرتد کے بجاے زندیق کے احکام کا اطلاق ہوگا؟
اس مقام پر پہنچ کر علامہ شامی ایک اور اہم تاویل کا تنقیدی تجزیہ پیش کرتے ہیں ۔ شیخ ابو السعود الآفندی سے روایت کی گئی ہے کہ گستاخ رسول پر عام مرتدین کے بجاے زندیق کے احکام کا اطلاق ہوگا جن میں ایک یہ ہے کہ اس کی ظاہری توبہ دنیوی سزا ساقط نہیں کرسکتی۔ صاحب در مختار کی تحقیق کے مطابق اس راے کی بنا یہ امر ہے کہ فقہا کے درمیان گستاخ رسول کی توبہ کی قبولیت و عدم قبولیت پر اختلاف اس صورت میں ہے جب اسے گرفتار نہ کیا گیا ہو ، اور یہ کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو پھر بالاتفاق اس کی توبہ سزا ساقط نہیں کرسکے گی کیونکہ اسے زندیق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں عثمانی خلیفہ کے ایک فرمان کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے جو ۹۳۴ ھ میں جاری کیا گیا تھا اور جس میں قرار دیا گیا تھا کہ اگر مجرم کی توبہ قاضی کو مطمئن کردے تو اسے سزاے موت کے بجاے تعزیری سزا دی جائے گی جیسا کہ امام اعظم کا مسلک ہے ، اور اگر قاضی مجرم کی توبہ سے مطمئن نہ ہو تو وہ اسے دیگر فقہا کی راے کے مطابق سزاے موت دے گا ۔
علامہ شامی کہتے ہیں کہ محقق ابوالسعود کے احترام اور ان کے ساتھ عقیدت کے باوجود کہنا پڑتا ہے کہ ان کے قول کے دو اجزا باہم متناقض ہیں کیونکہ پہلے جز میں قرار دیا گیا ہے کہ گرفتاری کے بعد مجرم کی توبہ کی عدم قبولیت پر کوئی اختلاف نہیں ہے ، جبکہ آخری جز میں تصریح کی گئی ہے کہ امام اعظم اور دیگر فقہا کا اختلاف گرفتاری کے بعد کے مرحلے پر ہے ۔ مزید برآں خود مفتی ابو السعود نے ایک اور فتوی میں قطعی الفاظ میں تصریح کی ہے کہ امام اعظم کا مسلک یہی ہے کہ مجرم کی گرفتاری کے بعد بھی اس کی توبہ قاضی کو مطمئن کردے تو وہ سزا کو ساقط کردے گا ۔
علامہ شامی نے اس بات کا بھی تفصیلی تجزیہ کیا ہے کہ کیا گستاخ رسول کو زندیق سمجھا جاسکتا ہے ؟ اور کیا اسے زندیق قرار دینے سے بزازی کا دیگر فقہاے احناف کے ساتھ اختلاف رفع ہوجاتا ہے ؟ انھوں نے واضح کیا ہے کہ اس مجرم کو زندیق قرار دینے سے ان تمام عبارات کی مخالفت لازم آتی ہے جن میں قرار دیا گیا ہے کہ وہ مرتد ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے ۔ اس عمومی حکم کی تخصیص تبھی مانی جاسکتی ہے جب ائمۂ مذہب سے اس کی روایت کی گئی ہو اور ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے ۔ نیز اگر یہ تخصیص مان لی گئی تب بھی بزازی اور ائمۂ مذہب کا اختلاف رفع نہیں ہوتا کیونکہ بزازی اور ان کے متبعین کی راے یہ ہے کہ گرفتاری سے قبل بھی اس مجرم کی توبہ ناقابل قبول ہے ۔ گویا اس تاویل کو ماننے سے دو آرا کا اختلاف رفع نہیں ہوتا بلکہ اس سے ایک تیسری راے وجود میں آجاتی ہے ۔
یہاں پھر علامہ شامی اس اصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب مذہب کے مجتہدین کے ساتھ متاخرین کا اختلاف ہو تو مجتہدین کی راے پر عمل لازم ہے ۔ اس لیے فتوی بزازی اور ان کے بعد آنے والوں کی راے کے بجاے ابو یوسف ، طحاوی اور دیگر ائمۂ مذہب کے موقف پر ہی دیا جائے گا ۔ حقیقی اختلاف تو اس صورت میں ہوتا جب ان ائمۂ مذہب کے مرتبے کے مجتہدین سے کوئی مختلف راے منقول ہوتی ۔ ( مثال کے طور پر ابو یوسف کچھ کہتے اور محمد کچھ اور ۔ ) اس صورت میں بھی ہمارا کام یہ نہ ہوتا کہ کسی ایک راے کی ترجیح کریں ، بلکہ یہ کام اصحاب ترجیح ہی کا ہوتا اور ہم پر ان کی اتباع لازم ہوتی ۔ اب جبکہ ائمۂ مذہب میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں تو ان سے مرتبے میں کم متاخرین نے خواہ ایک مختلف راے اختیار کی ہو اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے ۔
علامہ شامی اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ بزازی ، ابن الہمام ، ابن نجیم اور دیگر فقہا پر، جنھوں نے ائمۂ مذہب سے منقول موقف کے خلاف راے اختیار کی ہے، دیگر فقہاے مذہب کی جانب سے مسلسل تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ بہ الفاظ دیگر ان کے اختلاف کو مذہب کے اندر قبولیت عامہ حاصل نہیں ہوسکی ہے ۔
گستاخی کے ہر ملزم کو زندیق کیوں قرار نہیں دیا جاسکتا؟
پھر علامہ شامی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ گستاخی کے ہر ملزم کو زندیق کیوں قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ انھوں نے ابن الھمام کے حوالے سے زندیق کی یہ تعریف پیش کی ہے کہ زندیق سے مراد وہ شخص ہے جو کسی دین پر ایمان نہ رکھتا ہو اور جو عہد رسالت کے منافقین کی طرح ہو کہ بظاہر مسلمان ہو لیکن بباطن کافر ہو ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی پہچان صرف اسی وقت ہوسکتی ہے جب اس کا راز کسی طرح آشکارا ہوجائے ، یا وہ اپنے کسی ساتھی پر اپنا اصل عقیدہ واضح کرے ۔ یہاں البحر الرائق اور الخلاصۃ سے بعض جزئیات نقل کرنے کے بعد علامہ شامی التجنیس سے یہ اہم جزئیہ نقل کرتے ہیں کہ زندیق کی تین قسمیں ہیں :
۱۔ ایسا زندیق جو اصلاً مشرک ہو ؛
۲ ۔ ایسا زندیق جو پہلے مسلمان تھا ؛ اور
۳ ۔ ایسا زندیق جو پہلے ذمی تھا ۔
ان میں پہلی قسم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا ، الا یہ کہ وہ مشرکین عرب میں سے ہو۔ ( احناف کے نزدیک مشرکین عرب کے لیے دو ہی راستے ہیں : اسلام یا سزاے موت ۔ ) اسی طرح تیسری قسم کے زنادقہ سے بھی تعرض نہیں کیا جائے گا کیونکہ اہل ذمہ بھی غیر مسلم ہیں اور زنادقہ بھی ، اور الکفر ملۃ واحدۃ ۔ البتہ دوسری قسم کے زنادقہ ، جو پہلے مسلمان تھے ، کا حکم یہ ہے کہ انھیں اسلام قبول کرنے کو کہا جائے گا اور انکار پر انھیں سزاے موت دی جائے گی کیونکہ وہ مرتد ہو گئے ۔
علامہ کمال پاشا نے بھی تصریح کی ہے کہ ایسے زنادقہ اور مرتدین میں احکام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ۔ البتہ انھوں نے تنبیہ کی ہے کہ اگر اس قسم کے زنادقہ میں اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے مسلک کے لیے بہت مشہور ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہو تو اگر گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کرے تو اسے ارتداد کی سزا نہیں دی جائے گی لیکن اگر گرفتاری تک اس نے توبہ نہیں کی تو اسے سزاے موت دی جائے گی خواہ گرفتاری کے بعد وہ توبہ کرے ۔ علامہ شامی قرار دیتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس دوسری قسم کے زنادقہ میں جن کی توبہ گرفتاری کے بعد ان کی سزا کو ساقط نہیں کرسکتی ، یہ وہ مخصوص طبقہ ہے جن کو فساد پھیلانے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے ، بالکل اسی طرح جیسے جادوگروں ، ڈاکووں اور رہزنوں اور دیگر مفسدین کو سزاے موت دی جاتی ہے ۔
کیا گستاخی کے ہر ملزم کو زنادقہ کے اس مخصوص طبقے میں شامل سمجھا جاسکتا ہے ؟
اس مقام پر علامہ شامی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا گستاخی کے ہر ملزم کو زنادقہ کے اس مخصوص طبقے میں شامل سمجھا جاسکتا ہے ؟ وہ پھر یاد دلاتے ہیں کہ ان مخصوص زنادقہ کی سزاے موت کی علت ان کا کفر نہیں ، بلکہ یہ امر ہے کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کا مرتکب اپنا خبث باطن آشکارا کردیتا ہے اور اس کے ظاہری اسلام یا توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ، تو علامہ شامی اس بات کو نہیں مانتے ۔ وہ قرار دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر یہی حکم اس شخص کا بھی ہوتا جو رسول کے بجاے خدا کی شان میں گستاخی کرے ۔ نیز وہ یاد دلاتے ہیں کہ زنادقہ میں بھی یہ حکم صرف اس مخصوص طبقے کے لیے ہے جو اپنے مسلک کے لیے معروف ہو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہو ۔ گستاخی کا ہر مجرم اس نوعیت کا نہیں ہوتا ۔ علامہ شامی توجہ دلاتے ہیں کہ بسا اوقات اس جرم کا ارتکاب اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی شخص کو بہت زیادہ اشتعال دلایا جائے ۔ البتہ اگر مجرم اس فعل کے لیے معروف ہو اور وہ دوسروں کو بھی اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتا ہو تو پھر اس کے زندیق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اسے قطعی طور پر سزاے موت دی جائے گی خواہ وہ دعوی کرتا ہو کہ اس نے توبہ کرلی ہے ۔
تکفیر میں احتیاط کی ضرورت
یہاں پہنچ کر علامہ شامی اس اہم حقیقت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ کسی قول یا فعل کو کفر یا گستاخی قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اگر کسی قول یا فعل کی مناسب تاویل ممکن ہو تو اس کے مرتکب کو کافر یا گستاخ قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ اس سلسلے میں انھوں نے جامع الفصولین ، الفتاوی الصغری ، البزازیۃ ، التتارخانیۃ ، البحر الرائق اور خیر الدین الرملی کے فتاوی سے کئی جزئیات نقل کی ہیں ۔
ساری بحث کا خلاصہ
علامہ شامی نے ایک بہترین محقق کا کردار ادا کرتے ہوئے اس ساری بحث کا خلاصہ بھی اس مقام پر پیش کیا ہے ۔ چنانچہ وہ قرار دیتے ہیں کہ فقہاے احناف سے اس گستاخ رسول کے متعلق جو پہلے مسلمان تھا ، تین آرا نقل کی گئی ہیں :
۱ ۔ پہلی راے وہ ہے جس کی روایت امام ابو حنیفہ سے قاضی عیاض مالکی ، امام ابن تیمیہ حنبلی اور امام سبکی شافعی نے کی ہے کہ اس مجرم کی توبہ اس کی سزاے موت کو ساقط کردے گی خواہ اس نے توبہ گرفتاری سے قبل کی ہو یا بعد میں ۔ امام ابو حنیفہ سے اس راے کی روایت امام طبری نے بھی کی ہے ۔ یہ راے فقہاے احناف کے متقدمین کی مستند کتابوں میں بھی منقول ہے ۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس کی تصریح کی ہے اور یہی بات شرح الطحاوی میں بھی منقول ہے ۔ نیز حنفی مسلک کی معتبر متون کے مندرجات سے بھی اسی راے کی تائید ہوتی ہے ۔
۲ ۔ دوسری راے بزازیہ میں پیش کی گئی ہے کہ مجرم کی توبہ ، خواہ گرفتاری سے قبل ہو یا بعد میں ، ناقابل قبول ہے اور اس کی سزا توبہ سے ساقط نہیں ہوگی ۔ اس راے کی بنیاد حنفی مسلک کی اپنی روایت پر نہیں بلکہ قاضی عیاض کی الشفا اور امام ابن تیمیہ کی الصارم المسلول کی ان عبارات پر ہے جن میں امام ابو حنیفہ کا مسلک بیان کیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان عبارات کے فہم میں امام بزازی سے تسامح ہوا ہے ۔ یہ راے دراصل مالکی اور حنبلی فقہا کی ہے ۔ بزازی کے بعد اس راے پر اعتماد علامہ خسرو نے الدرر میں ، محقق ابن الھمام نے فتح القدیر میں ، ابن نجیم نے البحر الرائق اور الأشباہ میں ، علامہ تمرتاشی نے التنویر اور المنح میں ، شیخ خیر الدین الرملی نے اپنے فتاوی میں اور بعض دیگر متاخرین فقہا نے اپنی کتب میں کیا ہے ۔
۳ ۔ تیسری راے مفتی ابو السعود نے اختیار کی ہے کہ گرفتاری سے قبل اس شخص کی توبہ قابل قبول ہے لیکن گرفتاری کے بعد اس کی توبہ اسے سزاے موت سے نہیں بچا سکتی ۔
یہ بات بھی ثابت ہوچکی کہ بزازی اور ان کے متبعین کی راے پر دیگر فقہاے مذہب اس بنا پر مسلسل تنقید کرتے آئے ہیں کہ یہ راے حنفی مسلک کے مطابق نہیں ہے ۔ مفتی ابو السعود کی راے دراصل اس کوشش پر مبنی ہے کہ کسی طرح پہلی دو آرا میں تعارض کو رفع کیا جاسکے لیکن اس کوشش سے تعارض تو کیا رفع ہوتا ، ایک تیسری راے وجود میں آگئی ۔
ترجیح کے دس دلائل
بحث کے آخر میں علامہ شامی بعض مزید دلائل سامنے لاتے ہیں جن کی بنا پر وہ ان تین آرا میں پہلی راے کو ترجیح دیتے ہیں جو براہ راست ائمۂ مذہب سے منقول ہے ۔ جو دس دلائل یہاں علامہ شامی نے دیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے :
۱ ۔ ہم مقلد ہیں اور مقلد پر مجتہد کی راے کی اتباع واجب ہے ۔
۲ ۔ اس مسئلے میں امام کے ساتھ ابو یوسف اور محمد دونوں متفق ہیں جبکہ امام کے ساتھ صاحبین میں کسی ایک کی راے بھی موافق ہو تو حنفی مسلک میں اسی راے کی اتباع کی جاتی ہے ۔
۳ ۔ متقدمین اور متاخرین کے اختلاف کی صورت میں متقدمین کی راے کی اتباع ضروری ہے ۔
۴ ۔ متون اور شروح کے درمیان تعارض کی صورت میں متون کو ترجیح حاصل ہے اور اس مسئلے میں پہلی راے ہی متون کے مطابق ہے ۔
۵ ۔ اس جرم کا مرتکب اصلاً مسلمان تھا اور شہادتین کی وجہ سے اس کی جان کو عصمت حاصل تھی ۔ پس جو شخص اس کے خون کی حلت کا دعویدار ہے اس پر لازم ہے کہ اس حلت کے لیے قطعی دلیل لائے ۔ جس مجتہد کی اتباع ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دی ہے ان کی راے بھی اس حلت کے خلاف ہے ۔ ہم اپنے طور پر مجتہد بھی نہیں ہیں اور ایسے مجتہد کے مقلد بھی نہیں ہیں جو اس حلت کے قائل ہوں ۔
۶ ۔ کسی کو عدالتی کاروائی کے ذریعے مرتد قرار دینا ایک انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس لئے اس میں حتی الامکان احتیاط کی ضرورت ہے ۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت کے تقاضے اپنی جگہ، لیکن اس محبت کا اولین تقاضا ان کی شریعت کی اتباع ہے :
ان أمر الدم خطر عظیم حتی لو فتح الامام حصناً أو بلدۃً و علم أن فیھا مسلماً لا یحل لہ قتل أحد من أھلھا لاحتمال أن یکون المقتول ھو المسلم ۔ فلو فرضنا ان ھذہ النقول قد تعارضت فالأحوط فی حقنا أن لا نقتلہ لعدم الجزم بأنہ مستحق القتل ، فان الأمر اذا دار بین ترکہ مع استحقاقہ للقتل و بین قتلہ مع عدم استحقاقہ لہ تعین ترکہ لخطر الدماء ۔۔۔ و الأدلۃ فی ذلک متعارضۃ مع احتمالھا للتأویل بلا نص صریح ۔ و لیس لنا أن ننصب بآرائنا حدوداً و زواجر ۔ و انما کلفنا بالعمل بما ظھر أنہ من شرع نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم ۔ فحیث قال لنا : اقتلوا ، قتلنا ۔ وحیث قال : لا تقتلوا ترکنا ۔ و حیث لم نجد نصا قطعیاً و لا نقلاً عن مجتھدنا مرضیاً ، فعلینا أن نتوقف، ولا نقول ان محبتنا لنبینا صلی اللہ تعالی علیہ و سلم تقتضی أن نقتل من استطال علیہ و ان أسلم، لأن المحبۃ شرطھا الاتباع، لا الابتداع ۔ فاننا نخشی أن یکون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أول من یسألنا عن دمہ یوم القیامۃ ۔ فالواجب علینا الکف عنہ حیث أسلم، و حسابہ علی ربہ، العالم بما فی قلبہ، کما کان صلی اللہ تعالی علیہ و سلم یقبل الاسلام فی الظاھر، ویکل الأمر الی عالم السرائر ۔
[کسی کی جان کی حلت کا فیصلہ کرنا ایک سنگین معاملہ ہے ۔ یہاں تک کہ اگر امام کوئی قلعہ یا شہر فتح کرے اور اسے علم ہو کہ وہاں ایک مسلمان ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں میں کسی ایک کو بھی قتل کرے کیونکہ ہر شخص کے متعلق یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ شاید وہی مسلمان ہو ۔ پس اگر ہم نے یہ فرض کیا کہ ان نصوص کے درمیان تعارض ہے تو ہمارے حق میں زیادہ محتاط طریقہ یہی ہے کہ اسے سزاے موت نہ دیں کیونکہ اس کا سزاے موت کا مستحق ہونا قعطی نہیں ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے معاملے میں دو امکانات ہیں کہ یا تو اسے سزاے موت کا مستحق ہونے کے باوجود چھوڑ دیا جائے یا اسے مستحق نہ ہونے کے باوجود سزاے موت دی جائے تو جان لینے کی سنگینی کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا لازمی ہوگیا ۔۔۔ اور اس مسئلے میں دلائل کا آپس میں تعارض ہے اور ان میں کوئی نص صریح نہیں ہے بلکہ ہر ایک دلیل تاویل کا احتمال رکھتی ہے اور ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل کہ ہم اپنی آراء کی بنیاد پر حدود قائم کریں اور سزائیں دیں ، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت کا جو حکم ہم پر ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کریں ۔ پس اگر شریعت نے ہمیں کہا کہ سزاے موت دو تو ہم دیں گے اور اگر کہا کہ نہ دو تو نہیں دیں گے ، اور جہاں ہمیں کوئی قطعی نص نہ ملے ، نہ ہی ہمیں اپنے مجتہد کی جانب سے مقبول روایت ملے ، تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم رک جائیں ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر زبان دراز کرنے والے کو سزاے موت دیں کیونکہ ان کے ساتھ محبت کی شرط یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے نہ کہ اپنی جانب سے شریعت میں حکم کا اضافہ کیا جائے ، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن اس کے خون کے متعلق سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ ہی ہم سے نہ پوچھ لیں ! پس ہم پر واجب ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کرلیا تو ہم اسے سزاے موت دینے سے باز رہیں اور اس کے ساتھ حساب کا معاملہ اس کے رب پر چھوڑ دیں جو اس کے دل کی اندرونی کیفیت سے باخبر ہے ، جیسے رسول اللہ ﷺ لوگوں کے ظاہری اسلام کو قبول فرماتے تھے اور ان کے دلوں کا معاملہ رازوں سے باخبر ذات پر چھوڑ دیتے تھے ۔ ]
۷ ۔ اگر ہمارا مسلک یہ ہو کہ اس مجرم کو توبہ کے باوجود بہر صورت سزا دینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک سزاے موت کی علت خاص گستاخی کا فعل ہے، نہ کہ یہ امر کہ مسلمان گستاخی کے ارتکاب کی وجہ سے مرتد ہوجاتا ہے ۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہر گستاخ کو گستاخی کے فعل کی وجہ سے لازماً سزاے موت دی جائے گی ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیرمسلم ۔ تاہم یہ بات ہمارے مسلک کے اس صریح فیصلے کے خلاف ہوگی جس کی تصریح متون میں کی گئی ہے کہ گستاخی کے ارتکاب کی وجہ سے ذمی کا عقد نہیں ٹوٹتا ، اگرچہ حکمران بعض حالات میں اس کے فساد کے خاتمے کے لیے بطور سیاسہ اسے سزاے موت دے سکتا ہے ۔
۸ ۔ اگر خون کی حلت و حرمت کے متعلق دلائل میں تعارض ہو تو احناف کے ہاں ترجیح حرمت کی دلیل کو حاصل ہوگی ۔
۹ ۔ شبھۃ کی موجودگی میں حد ساقط ہوتی ہے ، جیسا کہ فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے ۔
۱۰ ۔ ابن ابی سرح کے واقعے سے بھی یہی حقیقت ثابت ہوتی ہے جنھوں نے ارتداد کا ارتکاب بھی کیا اور شان رسالت میں گستاخی بھی کی لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کو دربار رسالت میں لے آئے تو آپ نے بالآخر اس کی جانب سے توبہ اور اسلام کو دوبارہ قبول کرنے کا فعل قبول کرلیا ۔ اگر یہ حد کا معاملہ ہوتا جس میں معافی نہیں ہوتی ، نہ ہی رحم کی درخواست کی جاسکتی ہے تو رسول اللہ ﷺ کبھی ان کی بیعت قبول نہ کرتے ۔ یہ تاویل بھی صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے سے قبل ہی اس نے اسلام قبول کیا تھا کیونکہ جیسا کہ امام سبکی نے تصریح کی ہے یہ روایت اہل سیر کے ہاں غیر مقبول ہے ۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ابن ابی سرح آپ کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے اس کی بیعت قبول نہیں کی اور اسے امان نہیں دیا؟ انھوں نے جواب دیا : کیوں نہیں لیکن وہ اسلام سے قبل اپنے گناہوں کو یاد کرکے پچھتاتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا : اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے ۔ اسے معلوم ہوا کہ نہ صرف سزاے موت بلکہ گناہ بھی قبولیت اسلام کی وجہ سے دھل جاتا ہے ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سزا حق اللہ ہے ، نہ کہ حق العبد ، کیونکہ حق العبد ہونے کی صورت میں یہ سزا قبولیت اسلام پر ساقط نہ ہوتی ۔
کیا مجرم کو معاف کرنا رسول اللہ ﷺ کا ذاتی حق تھا ؟
بعض لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ کسی مجرم کو معاف کرنا یا نہ کرنا رسول اللہ ﷺ کا ذاتی حق تھا ، اس لیے آپ کی رحلت کے بعد کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ مجرم کو معاف کردے ، پس توبہ سے صرف گناہ ہی معاف ہوسکتا ہے ، دنیوی سزا ساقط نہیں ہوسکتی ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا حوالہ بھی بالعموم دیا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تو اسے سزاے موت دو۔
علامہ شامی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روایات میں مجرم کے لیے عفو کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اصطلاح شریعت میں گناہ کی معافی کے لیے نہیں بلکہ سزا کی معافی کے لیے رائج ہے ۔ نیز یہ بھی مسلّم ہے کہ رسول اللہ ﷺ انتہائی کریم تھے ، اپنی امت کی غلطیوں کے معاف کرنے میں نہایت رحم دل تھے اور ذاتی حق کے معاملے میں درگزر سے کام لیتے تھے، البتہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی ہوتی تو آپ وہاں سختی سے کام لیتے تھے ۔ جہاں تک مذکورہ حدیث کا تعلق ہے تو اس کی تاویل وہی ہے جو اسی نوعیت کی دوسری حدیث کی ہے : جس نے اپنا دین تبدیل کیا اسے سزاے موت دو ، یعنی اگر وہ توبہ نہ کرے ۔ یہی کچھ یہاں بھی کہا جائے گا کہ جس نے کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی اسے سزاے موت دو اگر وہ توبہ نہ کرے ۔
مزید برآں اس سزا کی علت خاص گستاخی کا فعل نہیں ہے بلکہ یہ امر ہے کہ گستاخی کی وجہ سے یہ شخص مرتد ہوجاتا ہے اور مرتد کی سزا موت ہے ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر گستاخ کے ذمی ہونے کی صورت میں بھی اسے لازماً یہ سزا دی جاتی حالانکہ مسلمہ طور پر ہمارا مسلک یہ نہیں ہے ۔ اگر گستاخی کو علت قرار دیا جائے تب بھی یہی کہا جائے گا کہ گستاخی سزاے موت کی علت اس وجہ سے ہے کہ گستاخی کا یہ فعل کفر و ارتداد کا موجب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ گستاخی بذات خود علت ہے خواہ وہ کفر و ارتداد کی موجب نہ ہو تو کیا وہ کسی ایسی صورت کا تصور کرسکتا ہے جس میں گستاخی تو ہو لیکن وہ گستاخی کفر و ارتداد کی موجب نہ ہو ؟
علامہ شامی یہاں پہنچ کر فریق مخالف کے دیگر دلائل کے بھی تفصیلی جواب دیے ہیں ۔
کعب بن الاشرف وغیرہ کی سزاے موت سے زیرنظر مسئلے میں استدلال باطل ہے ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کعب بن الاشرف ، ابو رافع ، ابن خطل اور اس نوعیت کے دیگر مجرموں کو یقیناًرسول اللہ ﷺ نے سزاے موت سنائی لیکن ان میں کسی بھی سزا سے مسئلۂ زیر بحث پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک کہ یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہوا تھا اور اس کے باوجود رسول للہ ﷺ نے اس کی سزاے موت برقرار رکھی ۔ ابن ابی سرح کے واقعے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سزا ساقط ہوجاتی ہے۔
جہاں تک مجرم کی سزاے موت پر اجماع کے دعوے کا تعلق ہے تو علامہ شامی نے واضح کیا ہے کہ یہ اجماع اس صورت میں ہے جب مجرم نے توبہ نہ کی ہو کیونکہ توبہ کی صورت میں سزاے موت کے وجوب و عدم وجوب پر فقہا کا اختلاف ایک مسلمہ حقیقت ہے ۔
اسی طرح علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ موقف صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ذاتی حق کا معاف کرنا بعد کے لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے جرائم معاف ہوجاتے ہیں تو گویا آپ نے تصریح کی کہ جس نے اسلام قبول کیا اسے میں نے معاف کردیا ۔ اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام سبکی نے نقل کیا کہ ہبار بن الاسود بن عبد المطلب کی سزاے موت کا رسول اللہ ﷺ نے حکم جاری کیا تھا لیکن انھوں نے آپ کے سامنے آکر اسلام کی قبولیت کا اعلان کیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تمھیں معاف کردیا اور اسلام پچھلے جرائم کو دھو دیتا ہے ۔ پس اگر گستاخی کو رسول اللہ ﷺ کے ذاتی حق پر عدوان سمجھا جائے تب بھی رسول اللہ ﷺ نے گویا اعلان عام فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو میں نے اسے معاف کردیا ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش کیا جاسکتا جب کسی شخص نے گستاخی کے بعد اسلام قبول کیا ہو اور پھر بھی اسے سزاے موت دی گئی ہو ۔
علامہ شامی مزید فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام قبول کرنے کی شرط پر اپنا حق معاف کردیا ہے تو آپ کا خلیفہ آپ کا حق نافذ کرنے کا مجاز نہیں رہا ۔ نیز اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا حق معاف نہیں فرمایا تب بھی خلیفہ صرف اسی صورت میں آپ کا حق نافذ کرسکتا ہے جب یہ ثابت کیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا حق نافذ کرنے کا اختیار خلیفہ کو دیا ہے ۔
اسلام پچھلے جرائم کو مٹا دیتا ہے
علامہ شامی کا اٹھایا گیا یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اگر اس سزاے موت کی بنیاد مصلحت عامہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اسے کبھی معاف نہ کرتے اور اگر اس کی بنیاد یہ امر ہوتا کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرکے اور دین کی توہین کرکے مجرم نے حق اللہ کی پامالی کی ہے تو اسلام قبول کرکے وہ اس جرم کو مٹا دیتا ہے ۔ یہاں علامہ شامی قرآن کریم کی بعض ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتد کی توبہ مقبول ہے ۔ بناے استدلال یہ امر ہے کہ یہ حکم تمام مرتدین کے لیے ہے جن میں گستاخ رسول بھی شامل ہے ۔ اسی طرح وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کا خون صرف تین میں سے کسی ایک امر کی بنیاد پر حلال ہوتا ہے : زانی محصن ، نفس بالنفس اور مرتد ۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ گستاخی کا مجرم جب اسلام قبول کرلیتا ہے تو وہ ان تین اصناف میں سے کسی صنف میں بھی شمار نہیں کیا جاسکتا ۔ علامہ شامی یہ نکتہ بھی اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزاے موت توبہ اور قبول اسلام سے ساقط ہوسکتی ہے تو یہی حکم رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے بھی ہے کیونکہ دونوں جرم ایک ہی نوعیت کے ہیں ۔
لوگوں کے دلوں میں جھانکنا ہماری ذمہ داری نہیں
علامہ شامی مزید فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ گستاخی کا ارتکاب کرکے مجرم قطعاً اپنا خبث باطن آشکارا کردیتا ہے کیونکہ جب وہ توبہ کرکے اسلام قبول کرلیتا ہے تو وہ اس بات کی نفی کردیتا ہے ۔ یہاں وہ ان آیات او ر احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ظاہری اسلام کو قبول کرنا چاہیے اور ان کے دل کے عقیدے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے ۔ یہی طرز عمل رسول اللہ ﷺ نے منافقین کے معاملے میں اختیار کیا تھا ۔
آخر میں علامہ شامی نہایت عجز و انکساری کے ساتھ قرار دیتے ہیں کہ ان کی اس تحقیق سے شاید ان کا دعوی قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا لیکن اس سے کم از کم شبھۃ تو پیدا ہوجاتا ہے جس کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کے لیے ، جو اپنے دین اور عزت کے بارے میں حساس ہو ، یہ جائز نہیں کہ وہ قطعیت کے ساتھ ایسے مجرم کی توبہ کی عدم قبولیت اور اس کی سزاے موت کے عدم سقوط کی بات کرے۔
فصل سوم : ذمی کی جانب سے گستاخی کا ارتکاب
مسلمان ، جو گستاخی کے نتیجے میں مرتد ہوجائے ، کے مسئلے کے تفصیلی تجزیے کے بعد علامہ شامی فصل سوم میں ذمی کی جانب اس جرم کے ارتکاب کے قانونی اثرات پر بحث کرتے ہیں ۔
ذمی کے متعلق امام ابو حنیفہ کا مسلک
اس فصل کی ابتدا میں علامہ شامی نے امام سبکی ، قاضی عیاض اور امام ابن تیمیہ کے طویل اقتباسات پیش کیے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے متعلق صراحت کی گئی ہے کہ وہ ذمی کے لیے تعزیری سزا کے قائل تھے اور سزاے موت کو اس کے لیے حد نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ جب ان کے شرک کے باوجود ان کے ساتھ عقد ذمہ کیا گیا تو اس کفر میں اضافے پر یہ عقد ٹوٹ نہیں سکتا لیکن فساد کے ارتکاب کی وجہ سے اسے مناسب سزا دی جاسکتی ہے ۔ اس کے بعد انھوں نے قرار دیا ہے کہ حنفی مسلک کی متون میں اسی بات کی تصریح کی گئی ہے جس کی روایت دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے یہ تین بڑے ائمہ کررہے ہیں ۔
بعض فقہاے احناف کی اختلافی راے
البتہ علامہ عینی نے امام شافعی کی راے کو اختیار کیا ہے کہ گستاخی سے ذمی کا عقد ٹوٹ جاتا ہے ۔ اسی طرح محقق ابن الہمام نے قرار دیا ہے کہ اگر ذمی ایسی بات کا کھلے عام اظہار کرے جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہو اور وہ ان کے عقائد کا حصہ بھی نہ ہو تو اس پر اس کا عقد ٹوٹ جاتا ہے اور اگر وہ اس بات کا کھلے عام اظہار نہ کرے، لیکن کسی طرح اس کی بات کی سن گن ملے تو اس پر عقد نہیں ٹوٹتا ۔ تاہم ابن الھمام کا یہ موقف حنفی مسلک کے صریح خلاف ہے اور اس وجہ سے ان کے شاگرد علامہ قاسم نے اپنے شیخ کی اس راے کی اتباع سے منع کیا ہے ۔ ابن نجیم نے بھی اس راے پر کڑی تنقید کی ہے ۔ اسی طرح ابن نجیم نے علامہ عینی کی بات کو بھی رد کیا ہے کیونکہ اس کے حق میں ائمۂ مذہب سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ علامہ خیر الدین الرملی نے دفاع کی کوشش اس طرح کی ہے کہ عدم نقض سے سزاے موت کا عدم لازم نہیں آتا ۔ انھوں نے ابن السبکی کے حوالے سے یہ بھی قرار دیا ہے کہ امام شافعی کا مسلک بھی اصلاً یہی ہے کہ گستاخی سے ذمی کا عقد نہیں ٹوٹتا لیکن اسے سزاے موت دی جاسکے گی ۔
اگر ذمی گستاخی کو عادت بنالے
اس کے بعد علامہ شامی نے مختلف کتب فقہ سے بہت ساری عبارات پیش کی ہیں جن کا مقتضا یہ ہے کہ ذمی اگر گستاخی کو عادت بنالے ، یا سرکشی کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کرے تو حنفی مسلک کے مطابق ایسے شخص کے فساد کے خاتمے کے لیے اسے بطور سیاسہ سزاے موت دی جاسکتی ہے ۔
عقد ذمہ نہ ٹوٹنے کے قانونی نتائج
علامہ شامی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ عقد ذمہ نہ ٹوٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے جبکہ اسے اس کے باوجود سزاے موت دی جاسکتی ہے ؟ انھوں نے دکھایا ہے کہ اگر اس کا عقد ٹوٹنے کی بات مانی جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اسے دیگر حربیوں کی طرح غلام بنایا جاسکے گا اور اس کا مال مسلمانوں کے لیے فے کی حیثیت رکھے گا ۔ گویا جب حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا لیکن اسے سزا دی جاسکے گی تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے حقوق شہریت حاصل رہیں گے اور ان کے بموجب اسے اور اس کے اموال کو دیگر امور سے قانونی تحفظ حاصل رہے گا، لیکن اس مخصوص جرم کے ارتکاب کی وجہ سے اسے اس جرم کی سزا دی جاسکے گی ۔
کیا ایسے مجرم کو سزاے موت نہیں دی جاسکے گی؟
بعض حنفی کتب میں قرار دیا گیا ہے کہ اس جرم کے بار بار ارتکاب پر بھی ذمی کو سزاے موت نہیں دی جائے گی ۔ علامہ شامی نے اس بات کا یہ جواب دیا ہے کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ اس جرم کا اظہار کھلے عام نہ کرتے ہوں ، گویا فساد نہ پھیلا رہے ہوں ، یا مراد یہ ہے کہ انھیں بطور حد سزاے موت نہیں دی جائے گی ، گویا سیاسۃً سزاے موت کی نفی اس سے نہیں ہوتی ۔ یہاں انھوں نے الملتقی سے یہ جزئیہ نقل کیا ہے کہ کوڑوں کی سزا کو رجم کی سزا کے ساتھ یا جلاوطنی کی سزا کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جائے گا ، الا یہ کہ فساد کے خاتمے کے لیے حکمران ان دو طرح کی سزاوں کو اکٹھا کرنے میں ہی مصلحت سمجھے ۔ نیز فقہا نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ سیاسہ پر مبنی حکم جاری کرنا حکمران کا اختیار ہے نہ کہ قاضی کا ۔ اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ ایسے مجرم کو سزاے موت نہیں دی جائے گی تو مراد یہ ہوتی ہے کہ قاضی اسے سزاے موت نہیں دے سکے گا ، الا یہ کہ حکمران اسے سیاسۃً ( یعنی فساد کے خاتمے کے لیے ) سزاے موت دینے کا فیصلہ کرلے۔
وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین۔
’’توہین رسالت کا مسئلہ‘‘ ۔ اعتراضات پر ایک نظر
محمد عمار خان ناصر
گزشتہ دنوں اپنی ایک تحریر میں توہین رسالت اور اس کی سزا کے حوالے سے ہم نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، بعض اہل قلم نے تحریری اور زبانی طو رپر اس پر مختلف تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان حضرات کے تحفظات کو درج ذیل تین نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے:
۱۔ ہم نے اپنی تحریر میں فقہاے احناف کے نقطہ نظر کی درست ترجمانی نہیں کی، کیونکہ توہین رسالت کے مجرم کے لیے کسی رعایت کے بغیر موت کی سزا کو لازم قرار دینے میں فقہاے احناف اور دوسرے فقہی مذاہب یک زبان ہیں۔
۲۔ توہین رسالت کے مجرم کے لیے کوئی قانونی رعایت یاموت سے کم تر سزا کی گنجائش تلاش کرنا دینی غیرت وحمیت کے منافی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت وعقیدت کی کمی کی دلیل ہے۔
۳۔ اگر فقہی لٹریچر میں اس ضمن میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو بھی ایک ایسے ماحول میں اس بحث کو چھیڑنا جس میں مغرب اور مغرب زدہ طبقے قانون ناموس رسالت کے خاتمے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، درحقیقت اس مسئلے میں مغرب کے موقف کو تائید فراہم کرنے اور مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔
آئندہ سطور میں، ہم ان اعتراضات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔
فقہاے احناف کا نقطہ نظر
بہت سے قارئین کے لیے، جنھوں نے ہماری اصل تحریر کا مطالعہ کیا ہے، یہ اعتراض شاید اس حوالے سے حیرت کا موجب ہو کہ ہم نے اپنی تحریر میں فقہا ے احناف کی طرف اس موقف کی نسبت کا محض دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مستند ترین علمی مصادر سے اس کی تائید میں تفصیلی حوالہ جات بھی نقل کیے ہیں۔ تاہم یہ اعتراض پیدا ہونے کی ایک خاص وجہ ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس وقت مذہبی رسائل وجرائد اور اخباری کالموں میں جو اہل قلم دینی موضوعات پر امت کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان میں سے بیشتر کو نہ تو اسلامی علوم کے اعلیٰ مآخذ تک براہ راست رسائی حاصل ہے اور نہ علمی وفقہی موضوعات پر امت مسلمہ کی علمی روایت اور اس کے مختلف رجحانات کا باریک بینی سے مطالعہ اور تجزیہ کرنے کی فرصت میسر ہے۔ چونکہ توہین رسالت کی سزا کے ضمن میں فقہاے احناف کا موقف بعض تکنیکی فقہی نکتوں پر مبنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احناف کی علمی روایت میں ایک سے زیادہ فقہی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے جن حضرات کو زیادہ توجہ سے احناف کے فقہی لٹریچر کا مطالعہ وتجزیہ کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ بعض آرا اور عبارات کے درست پس منظر سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی الجھی ہوئی تحریریں عام قارئین کے سامنے پیش کر کے ان کے ذہنوں میں بھی کنفیوژن پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فقہاے احناف کے موقف کی کچھ مزید توضیح قارئین کے سامنے رکھ دی جائے۔
اس ضمن میں حنفی فقہا کے ہاں پائے جانے والے مختلف رجحانات کو حسب ذیل نکات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے:
۱۔ فقہاے احناف کا کلاسیکی موقف یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جزیہ ادا کرنے کی شرط پر اسلامی ریاست کی شہریت قبول کر لے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کو برا بھلا کہنے سے اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے اسے تادیب اور تنبیہ کے طو رپر سزا تو دی جائے گی، لیکن نقض عہد کی بنیاد پر مباح الدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ احناف کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب وشتم کفر ہی کی ایک شکل ہے جس پر قائم رہنے کی اجازت عقد ذمہ کی صورت میں غیر مسلموں کو پہلے ہی دی جا چکی ہے، اس وجہ سے شتم رسول کے ارتکاب کو فی نفسہٖ معاہدہ توڑنے کے ہم معنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ (کاسانی، بدائع الصنائع، ۷/۱۱۳)
اس کے مقابلے میں بعض حنفی اہل علم مثلاً جصاص، ابن الہمام اور آلوسی رحمہم اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب وشتم کے ارتکاب کے باوجود معاہدۂ ذمہ کو علی حالہ برقرار سمجھنا درست نہیں، کیونکہ معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اہل ذمہ مسلمانوں کے مقابلے میں ذلیل اور پست ہو کر رہیں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرنے والا ذمی معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے مباح الدم ہو جاتا ہے۔ (جصاص، احکام القرآن ۴/۲۷۵۔ ابن الہمام، فتح القدیر، ۲/۶۲)
ہمارے نزدیک اس باب میں یہ دوسرا نقطہ نظر ہی راجح ہے، اس لیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے میں انھیں ان کے کفریہ اور مشرکانہ اعتقادات پر قائم رہنے کی اجازت تو دی گئی تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت ہرگز اس معاہدے کا حصہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود فقہاے احناف غیر مسلموں کے کفر وشرک پر تو انھیں کوئی سزا دینے کے قائل نہیں، لیکن توہین رسالت کو ایک قابل تعزیر جرم قرار دیتے ہیں جس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں بنتا کہ معاہدے کی رو سے انھیں ایسا کرنے کی اجازت حاصل نہیں تھی۔ آلوسی نے جمہور احناف کی راے پر تنقید کرتے ہوئے بجا طو رپر لکھا ہے کہ:
والقول بان اہل الذمۃ یقرون علی کفرہم الاصلی بالجزیۃ وذا لیس باعظم منہ فیقرون علیہ بذلک ایضا .... لیس من الانصاف فی شئ ویلزم علیہ ان لا یعزروا ایضا کما لا یعزرون بعد الجزیۃ علی الکفر الاصلی وفیہ لعمری بیع یتیمۃ الوجود بثمن بخس (روح المعانی ۱۰/۵۸، ۵۹)
’’یہ کہنا کہ چونکہ جزیہ کی ادائیگی کے بعد اہل ذمہ کو ان کے کفر اصلی پر قائم رہنے کی اجازت دی جاتی ہے اور سب وشتم، اس کفر سے زیادہ بڑا جرم نہیں ہے، اس لیے انھیں اس پر بھی قائم رہنے دیا جائے گا، انصاف سے بالکل بعید بات ہے۔ اس صورت میں تو یہ لازم آئے گا کہ جیسے انھیں جزیہ ادا کرنے کے بعد ان کے کفر اصلی پر کوئی تعزیر نہیں کی جاتی، اسی طرح سب وشتم پر بھی کوئی تعزیری سزا نہ دی جائے۔ بخدا، یہ تو کائنات کے در یتیم کو نہایت حقیر قیمت کے عوض فروخت کر دینے کے مترادف ہے۔‘‘
۲۔ فقہ حنفی کے کلاسیکی مآخذ میں سب وشتم کے مرتکب ذمی کے بارے میں صرف تادیبی سزا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے، جبکہ سزاے موت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ سب وشتم کرنے والے ذمی کو صرف زبانی تنبیہ کی جائے، جبکہ اس کے بعد اگر وہ اس کا مرتکب ہو تو بھی اسے قتل کرنے کے بجائے تادیبی سزا ہی دی جائے۔ (مختصر الطحاوی، ص ۲۶۲)
فقہ حنفی کے اس کلاسیکی موقف کے تقابل میں متاخرین میں سے بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قتل سے کم تر تعزیری سزا سب وشتم کے جرم سے باز رکھنے میں زیادہ موثر نہیں، اس لیے تعزیر کے طور پر ایسے مجرم کو قتل ہی کی سزا دی جانی چاہیے۔
یہاں دو نکتے ملحوظ رہنے چاہییں:
ایک یہ کہ فقہ حنفی کے کلاسیکی مآخذ کی عبارات میں ذمی پر سزاے موت کے عدم نفاذ کا موقف بظاہر کسی قید کے بغیر بالکل مطلق انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کسی حال میں بھی شاتم رسول کو سزاے موت نہیں دی جا سکتی۔ علامہ ابن نجیم نے علامہ عینی اور ابن الہمام کی طرف سے شاتم رسول کے لیے سزاے موت کے حق میں رجحان ظاہر کرنے پر جو تنقید کی ہے، اس سے بھی بظاہر اس تاثر کی تائید ہوتی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے:
ان قول العینی واختیاری ان یقتل بسب النبی لا اصل لہ فی الروایۃ وکذا وقع لابن الہمام بحث ہنا خالف فیہ اہل المذہب وقد افاد العلامۃ قاسم فی فتاواہ انہ لا یعمل بابحاث شیخہ ابن الہمام المخالفۃ للمذہب نعم نفس المومن تمیل الی قول المخالف فی مسالۃ السب لکن اتباعنا للمذہب واجب وفی الحاوی القدسی ویودب الذمی ویعاقب علی سبہ دین الاسلام او النبی او القرآن (البحر الرائق ۵/۱۲۵)
’’علامہ عینی کا یہ کہنا کہ میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے پر ذمی کو قتل کیا جائے، حنفی مذہب میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ اسی طرح ابن الہمام نے بھی یہاں ایک ایسی بحث کی ہے جس میں انھوں نے حنفی فقہا سے مختلف موقف اختیار کیا ہے۔ علامہ قاسم بن قطلوبغا نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ان کے استاذ علامہ ابن الہمام کی جو بحثیں حنفی مذہب کے مخالف ہوں، ان پر عمل نہ کیا جائے۔ ہاں، ایک مسلمان کا دل سب وشتم کے مسئلے میں مخالف قول کی طرف رجحان محسوس کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے حنفی مذہب کی پیروی کرنا واجب ہے۔ حاوی قدسی میں ہے کہ دین اسلام یا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے پر ذمی کو تادیب کے طور پر سزا دی جائے گی۔‘‘
تاہم علامہ شامی اور صاحب اعلاء السنن نے واضح کیا ہے کہ احناف کے موقف کو سزاے موت کی مطلقاً نفی پر محمول کرنا درست نہیں اور یہ کہ ان کے موقف کا اصل رخ سزاے موت کے امکان کی نفی کی طرف نہیں، بلکہ اسے ایک لازم وواجب سزا قرار دینے کی نفی کی طرف ہے۔ (مجموعہ رسائل ابن عابدین ۱/۳۵۳، ۳۵۴۔ اعلاء السنن ۱۲/۵۰۵ تا ۵۱۴)
بہرحال اتنی بات بالکل واضح ہے کہ حنفی فقہا کا اصل رجحان غیر مسلموں کو سزاے موت نہ دینے کی طرف ہے، جبکہ متاخرین کے ہاں ایسے مجرموں کو تعزیراً قتل کرنے کا رجحان عملی مصلحت کے تحت زیادہ نمایاں ہوا ہے۔
دوسرا نکتہ یہ سامنے رہنا چاہیے کہ متاخرین میں سے جو حضرات غیر مسلموں کے لیے تعزیری طور پر سزاے موت کے قائل ہیں، ان کا موقف بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسے مجرم کو توبہ اور اصلاح کا موقع دینے کی کوئی گنجائش نہیں اور پہلی ہی مرتبہ اس جرم کا ارتکاب کرنے پر یا جرم کے ارتکاب کے بعد ندامت ظاہر کرنے کے باوجود اسے موت کی سزا دینا ضروری ہے۔ اس کے بالکل برعکس یہ حضرات اس کے قائل ہیں کہ ایسے مجرم کو سمجھا بجھا کر اس جرم کے ارتکاب سے باز رہنے کی تلقین کرنی چاہیے اور کسی شخص کو اسی وقت قتل کرنا چاہیے جب وہ اپنی روش بدلنے پر آمادہ نہ ہو۔ چنانچہ ابن الہمام لکھتے ہیں:
ہذا البحث منا یوجب انہ اذا استعلی علی المسلمین علی وجہ صار متمردا علیہم حل للامام قتلہ او یرجع الی الذل والصغار (فتح القدیر ۶/۶۲، ۶۳)
’’ہماری اس بحث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ذمی (سب وشتم کی صورت میں) مسلمانوں کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے ہوئے باغیانہ روش اختیار کر لے تو حکمرا ن کے لیے اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ دوبارہ ذلت اور پستی کی حالت قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔‘‘
ملا احمد جیون بھی اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:
والحق ان یکون فتوی اہل العلم فی زماننا علی ہذا اذ لیس فی التعزیر الذی قال ابو حنیفۃ تہدید بحسب ما کان ذلک فی القتل (التفسیرات الاحمدیہ، ص ۴۵۲)
’’حق بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اہل علم کو اسی پر فتویٰ دینا چاہیے، کیونکہ امام ابوحنیفہ جو تعزیری سزا تجویز کرتے ہیں، وہ اس جرم سے روکنے میں اتنی موثر نہیں جتنی قتل کی سزا موثر ہے۔‘‘
لیکن اسی بحث میں انھوں نے تصریح کی ہے کہ ذمی کو علی الفور قتل کرنے کے بجائے اسے سمجھا بجھا کر اس طرز عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ لکھتے ہیں:
ان من طعن فی الدین ای سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجب ان یذاکر معہ فان قبل الذمۃ وکتم ما اظہرہ یترک والا یقتل البتۃ (التفسیرات الاحمدیہ، ص ۴۵۳)
’’جو شخص دین میں طعن کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنا واجب ہے۔ اگر وہ دوبارہ عہد ذمہ قبول کر لے اور جن باتوں کا اظہار کرتا ہے، انھیں علانیہ کہنا چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دیا جائے، ورنہ اسے لازماً قتل کر دیا جائے۔‘‘
علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:
من کان کافرا خبیث الاعتقاد وتجاہر بالشتم والالحاد ثم لما رای الحسام بادر الی الاسلام فلا ینبغی لمسلم التوقف فی قتلہ وان تاب لکن بشرط تکرر ذلک منہ وتجاہرہ بہ کما علمتہ مما نقلنا عن الحافظ ابن تیمیۃ عن اکثر الحنفیۃ ومما نقلناہ عن المفتی ابی السعود (رسائل ابن عابدین ۱/۳۵۶)
’’جو شخص کافر ہو اور خبیث اعتقادات رکھتا ہو اور کھلم کھلا سب وشتم اور الحاد کی باتیں کرے، لیکن جب تلوار دکھائی دے تو فوراً اسلام کی طرف لپک پڑے، ایسے شخص قتل کو کرنے کے بارے میں کسی مسلمان کو توقف نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ توبہ کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے یہ جرم بار بار اور لوگوں کے سامنے علانیہ کیا ہو، جیسا کہ ہم نے حافظ ابن تیمیہ کے حوالے سے اکثر احناف کا موقف اور اس کے علاوہ مفتی ابوالسعود کا فتویٰ نقل کیا ہے۔‘‘
۳۔ اگر کسی مسلمان سے سب وشتم کا جرم سرزد ہوجائے تو متقدمین ائمہ احناف کا متفقہ موقف یہ ہے کہ اس کا حکم وہی ہے جو کسی بھی مرتد کا ہوتا ہے، چنانچہ اس سے توبہ کے لیے کہا جائے گا اور اگر وہ توبہ کر لے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس بعض متاخرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سب وشتم کے ارتکاب کی وجہ سے مرتد ہو جائے تو اس کے لیے دنیوی قانون کے لحاظ سے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور اس جرم کی پاداش میں اسے ہر حال میں قتل کر دینا لازم ہے۔ یہ موقف متاخرین میں سے بزازی، تمرتاشی، ابن ہمام اور ابن نجیم وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔
اس نقطہ نظر کے حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی نے اپنی تصنیف ’تنبیہ الولاۃ والحکام‘ میں پوری تحقیق کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ حنفی فقہ میں اس کی سرے سے کوئی بنیاد موجود نہیں اور یہ کہ یہ موقف اصل میں بزازی کے ہاں قاضی عیاض کی ’الشفاء‘ کی ایک عبارت کا بالکل غلط مطلب سمجھنے سے پیدا ہوا اور پھر بعد میں آنے والے بعض حضرات بزازی ہی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اسی موقف کو نقل کرتے چلے گئے۔ ’شرح عقود رسم المفتی‘ میں لکھتے ہیں:
قد نقل صاحب الفتاوی البزازیۃ انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل توبتہ وان اسلم وعزا ذلک الی الشفاء للقاضی عیاض المالکی والصارم المسلول لابن تیمیۃ الحنبلی ثم جاء عامۃ من بعدہ وتابعہ علی ذلک وذکروہ فی کتبہم حتی خاتمۃ المحققین ابن الہمام وصاحب الدرر والغرر مع ان الذی فی الشفاء والصارم المسلول ان ذلک مذہب الشافعیۃ والحنابلۃ واحدی الروایتین عن الامام مالک مع الجزم بنقل قبول التوبۃ عندنا وہو المنقول فی کتب المذہب المتقدمۃ ککتاب الخراج لابی یوسف وشرح مختصر الامام الطحاوی والنتف وغیرہا من کتب المذہب (مجموعہ رسائل ابن عابدین ۱/۱۴)
’’فتاویٰ بزازیہ میں منقول ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا قتل واجب ہے اور توبہ قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ اسلام قبول کر لے۔ صاحب بزازیہ نے یہ بات قاضی عیاض مالکی کی الشفاء اور ابن تیمیہ حنبلی کی الصارم المسلول کی طرف منسوب کی ہے۔ پھر بزازی کے بعد آنے والے اکثر حضرات نے، یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین علامہ ابن الہمام اور الدرر والغرر کے مصنف نے بھی یہی بات اپنی کتابوں میں لکھ دی، حالانکہ الشفاء اور الصارم میں جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شوافع اور حنابلہ کا مذہب ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے، جبکہ ہمارا (احناف کا) مذہب قطعیت کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ مقبول ہے اور یہی بات قدماء احناف کی کتابوں، مثلاً امام ابو یوسف کی کتاب الخراج، امام طحاوی کی مختصر کی شرح اور النتف وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔‘‘
یہاں یہ اہم نکتہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بزازی، تمرتاشی، ابن ہمام اور ابن نجیم وغیرہ توبہ قبول کیے بغیر شاتم رسول کو قتل کرنے کا جو حکم بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق صرف مسلمان سے ہے اور غیر مسلم شاتم رسول ان حضرات کے نزدیک اس کے دائرۂ اطلاق میں نہیں آتا، چنانچہ اہل ذمہ کے بارے میں یہ حضرات بھی، فقہ حنفی کے کلاسیکی موقف کے مطابق، اسی بات کی تصریح کرتے ہیں کہ سب وشتم کے ارتکاب پر معاہدۂ ذمہ نہیں ٹوٹتا اور چونکہ اہل ذمہ پہلے ہی کفر پر قائم ہیں، اس لیے سب وشتم کی صورت میں مزید کفر کے ارتکاب پر انھیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طو رپر صاحب ’تنویر الابصار‘ علامہ تمرتاشی نے سب وشتم کے مرتکب مسلمان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں اور اسے قتل کیا جائے گا (الدر المختار ۴/۲۳۲) جبکہ اہل ذمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سب وشتم سے ان کا معاہدہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے انھیں قتل کرنے کے بجائے تادیبی سزا دی جائے گی:
ویودب الذمی ویعاقب علی سبہ دین الاسلام او القرآن والنبی صلی اللہ علیہ وسلم (الدر المختار ۴/۲۱۴)
’’دین اسلام یا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے پر ذمی کو تادیب کے طور پر سزا دی جائے گی۔‘‘
اسی طرح علامہ ابن الہمام نے سب وشتم کی وجہ سے مرتد ہو جانے والے مسلمان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں اور اسے ہر حال میں قتل کیا جائے گا (فتح القدیر ۶/۹۸) لیکن اہل ذمہ کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ’حل للامام قتلہ او یرجع الی الذل والصغار‘، یعنی امام کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے، الا یہ کہ وہ اپنی روش سے باز آکر دوبارہ ذلت اور پستی کی حالت قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے واضح ہے کہ وہ توبہ کر لینے کی صورت میں ذمی کے قتل کو لازم نہیں سمجھتے۔
یہی معاملہ علامہ ابن نجیم کا ہے۔ انھوں نے سب وشتم کے مرتکب مسلمان کی توبہ کو ناقابل قبول اور مجرم کو ہر حال میں واجب القتل کہا ہے، (البحر الرائق ۵/۱۳۶) لیکن اہل ذمہ کے بارے میں لکھتے ہیں:
ولا ینتقض عہدہ بالاباء عن الجزیۃ والزنا بمسلمۃ وقتل مسلم وسب النبی لان الغایۃ التی ینتہی بہا القتال التزام الجزیۃ (البحر الرائق ۵/۱۲۴)
’’ذمی اگر جزیہ دینے سے انکار کرے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ بدکاری کرے یا کسی مسلمان کو قتل کر دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے تو اس سے اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ غایت جس پر قتال رک جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ذمی جزیہ ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لے۔‘‘
ابن نجیم نے اسی بحث میں عینی اور ابن الہمام کے اس قول پر تنقید کرتے ہوئے جس میں انھوں نے سب وشتم کے مرتکب ذمی کو قتل کرنے کو راجح قرار دیا ہے، اسے خلاف مذہب قرار دیا ہے۔ (ان کا متعلقہ اقتباس اوپر نقل کیا جا چکا ہے)۔
فقہاے احناف کے ہاں پائے جانے والے ان مختلف رجحانات کے تقابل اور موازنہ سے ایک بنیادی نکتہ یہ سامنے آتا ہے کہ بہت سے پہلووں سے زاویہ نظر کے اختلاف کے باوجود سب وشتم کے مرتکب غیر مسلم کے بارے میں ان کے ہاں اس بات پر قریب قریب اتفاق پایا جاتا ہے کہ اسے اس جرم پر اگر قتل کی سزا دی جائے گی تو دراصل سرکشی اور عناد کے رویے کی وجہ سے دی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں، جرم کے ارتکاب کے بعد ندامت محسوس کرنے اور توبہ ومعذرت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے معافی کی گنجائش تسلیم کرنے پر فقہاے احناف قاطبۃً متفق ہیں اور مذکورہ مختلف رجحانات میں سے کسی بھی رجحان کی نمائندگی کرنے والے اہل علم کو اس پر اصرار نہیں ہے کہ غیر مسلم کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیے بغیر نفس جرم کے ارتکاب پر قتل کر دینا ضروری ہے۔
معاصر تناظر میں اس مسئلے پر خامہ فرسائی کرنے والے بیشتر اہل قلم کے ہاں احناف اور جمہور فقہا کے موقف میں موافقت اور ہم آہنگی ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا طرز استدلال دیکھنے کو ملتا ہے جس میں اس پوری تفصیل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طو رپر بعض حضرات متاخرین احناف مثلاً علامہ ابن الہمام وغیرہ کے ایسے فتوے نقل کر کے جن میں سب وشتم کے مرتکب ذمی کو تعزیراً قتل کرنے کو راجح قرار دیا گیا ہے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کا اصل موقف ہے، حالانکہ خود ان حضرات کی تصریح کے مطابق ان کی یہ راے احناف کے روایتی موقف کی ترجمانی نہیں کرتی، بلکہ اس سے اختلاف پر مبنی ہے۔ مزید یہ کہ متاخرین میں سے یہ رائے اختیار کرنے والے حضرات اس کی بھی تصریح کرتے ہیں کہ سب وشتم کے ارتکاب پر ذمی کے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے اور مجرم کو اسی صورت میں قتل کیا جائے جب وہ تنبیہ وتادیب کے باوجود اپنی روش سے باز نہ آئے اور سرکشی اور عناد ہی کے رویے پر مصر رہے، جیسا کہ ابن الہمام، ابن عابدین اور ملا جیون کی تصریحات سے واضح ہے۔
اسی طرح بعض حضرات احناف اور جمہور کے موقف میں یکسانی دکھانے کے لیے بزازی اور ابن نجیم وغیرہ کی ایسی عبارات کا حوالہ دیتے ہیں جن کی رو سے سب وشتم کے مرتکب کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ مذکورہ فقہا کا یہ موقف متقدمین ائمہ احناف کی تصریحات کے بالکل برعکس ہے۔ پھر یہ کہ بزازی وغیرہ کا یہ موقف سب وشتم کے مرتکب مسلمان کے بارے میں ہے نہ کہ غیر مسلم کے بارے میں، اس لیے توبہ کی گنجائش تسلیم نہ کرنے کو علی الاطلاق بیان کرنا اور غیر مسلم شاتم رسول کو بھی توبہ کا موقع دیے بغیر واجب القتل قرار دینا خود ان حضرات کے نقطہ نظر کی درست ترجمانی نہیں ہے۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ ظلم علامہ شامی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ان کی تصانیف سے وہ جملے نقل کر کے جن میں انھوں نے بزازی وغیرہ کا موقف بیان کیا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علامہ شامی بھی سب وشتم کے مرتکب کے لیے توبہ کی گنجائش کے قائل نہیں، حالانکہ ابن عابدین نے رد المحتار اور تنبیہ الولاۃ والحکام میں جو بحث کی ہے، وہ سر تا سر اس نقطہ نظر کی تردید پر مبنی ہے۔
اسلامی غیرت وحمیت کا سوال
اب دوسرے اعتراض کو دیکھیے:
ہمارے نزدیک یہ اعتراض اس جذباتی انداز فکر کا ایک شاخسانہ ہے جس میں اس وقت مسلمانوں کے ’عوامی‘ راہ نماؤں نے انھیں مبتلا کر رکھا ہے اور جو انھیں اس پر برانگیختہ کرتا ہے کہ وہ دینی غیرت وحمیت کا اپنا ایک مخصوص مفہوم طے کریں اور دینی معاملات میں خالصتاً جذبات کو فیصلہ کن حیثیت دیتے ہوئے فقہ وشریعت کی تعبیر کے مسائل کو بھی اسی ذہنی رجحان کے تحت دیکھنا شروع کر دیں اور ایسا کرتے ہوئے خود اپنی تاریخ اور اپنی ہی مستند دینی وعلمی روایت کے ان تمام پہلووں کو نظر انداز کر دیں بلکہ بے غیرتی وبے حمیتی کا مظہر قرار دے دیں جو اس وقت کی ذہنی فضا میں لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔
اس طرز فکر کے حاملین سے ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ تاریخ کے صرف ایسے واقعات کا حوالہ دینے کے بجائے جو بظاہر ان کے تصور غیرت وحمیت سے زیادہ ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں، درج ذیل واقعات کو بھی ملحوظ رکھیں اور غیرت وحمیت کے اس مفہوم کو دینی لحاظ سے حتمی اور معیاری سمجھنے کے بجائے جو انھوں نے اپنے ذہن میں طے کر رکھا ہے، اس معاملے کے حکیمانہ پہلووں کو بھی پورا وزن دیں۔
★ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی اور آپ کی توہین کیا کرتی تھی اور اپنے مالک کے منع کرنے اور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود اس سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن اسی بات پر اس نے اشتعال میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ (ابوداؤد، ۴۳۶۱)
عمیر بن امیہ کی بہن نے، جو مشرک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں سب وشتم کو ایک مستقل روش بنا رکھا تھا اور اس کے اس رویے سے تنگ آ کر ایک دن عمیر نے اسے قتل کر دیا تھا۔ (طبرانی، مجمع الزوائد ۶/۲۶۰۔ ابن ابی عاصم، الدیات، ۱/۷۳)
ان واقعات میں صحابہ نے پہلے مرحلے پر ان مجرموں کے خلاف قتل جیسا انتہائی اقدام کرنے کے بجائے ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے اور سمجھا بجھا کر اس روش سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ کیا ناقدین اس طرز عمل کو دینی غیرت کے منافی قرار دیں گے؟
★ واقعہ افک میں عبد اللہ بن ابی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف تہمت طرازی کا جو طوفان کھڑا کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر اذیت ناک بن گیا کہ آپ کو لوگوں سے اپیل کرنا پڑی کہ وہ اس کے شر سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچائیں۔ اس موقع پر اوس کے سردار سعد بن معاذ نے عبد اللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تو ابن ابی کے قبیلہ، بنو خزرج کے سردار سعد بن عبادہ سخت غصے میں آ گئے اور انھوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ ’’خدا کی قسم، تم اسے قتل نہیں کرو گے اور نہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ اسے قتل کر سکو۔ اگر اس کا تعلق تمھارے قبیلے سے ہوتا تو تم کبھی اس کا قتل کیا جانا پسند نہ کرتے۔‘‘ (بخاری، ۳۹۱۰)
اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ ناقدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی محبت وعقیدت کے بارے میں کوئی سوال اٹھانے کی جسارت نہیں کریں گے۔
★ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے افراد کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان کے رضاعی بھائی عبد اللہ بن ابی سرح کو عام معافی سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ تاہم سیدنا عثمان نے اسے اپنے پاس چھپا لیا اور حالات کے پر سکون ہونے پر اسے اپنے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے حد اصرار کر کے اس کے لیے معافی کا فیصلہ کروایا۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۵/۶۹، ۷۰۔ الصارم المسلول، ص ۱۰۸)
اگر دینی حمیت کے اسی تصور کو معیار سمجھا جائے جو ناقدین بیان کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مبہم اعلان کے باوجود سیدنا عثمان کی طرف سے ابن ابی سرح کو اپنے پاس چھپانے، پناہ دینے اور پھر اصرار کر کے اسے معافی دلوانے کے اس عمل کی کیا توجیہ کیا جائے گی؟
★ سیدنا معاویہ کی مجلس میں ابن یامین نضری نے کہا کہ اسے بد عہدی کرتے ہوئے قتل کیا گیا تھا، لیکن سیدنا معاویہ نے اس بیان پر ابن یامین کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، بلکہ محمد بن مسلمہ کے احتجاج کے باوجود، جو اسی مجلس میں موجود تھے، ابن یامین پر سزاے موت نافذ کرنا تو کجا، کوئی تادیبی اقدام تک نہیں کیا۔ (بیہقی، دلائل النبوۃ ۳/۱۹۳)
روایت میں سیدنا معاویہ کے اس طرز عمل کی وجہ بیان نہیں ہوئی، لیکن یقینی طور پر ان کے پیش نظر اس کی کوئی نہ کوئی دینی مصلحت تھی۔ اب اگر ناقدین کے تصور حمیت کو معیار مانا جائے تو کیا اس واقعے سے سیدنا معاویہ کے دین وایمان کے بارے میں اس سے مختلف کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے جو مثال کے طور پر اہل تشیع کرتے ہیں؟
★ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے مالک بن نویرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر استخفاف آمیز اندازمیں کیا تو خالد بن ولید نے کسی توقف کے بغیر اسے وہیں قتل کروا دیا۔ تاہم ان کے اس اقدام پر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے سخت اعتراض کیا، سیدنا عمر نے سیدنا ابوبکر سے سفارش کی کہ خالد کو معزول کر دیا جائے، جبکہ خود سیدنا ابوبکر نے مالک بن نویرہ کے بھائی کو اس کی دیت ادا کی۔ (ابن کثیر ، البدایہ والنہایہ ۶/۳۲۲)
غور طلب بات یہ ہے کہ مروجہ تصورات کے مطابق خالد بن ولید کا فیصلہ دینی غیرت وحمیت سے زیادہ ہم آہنگ بلکہ اس کا عین تقاضا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے اس غیرت مندانہ اقدام پر تین اکابر صحابہ ان سے نالاں ہوئے اور ان کے فیصلے کا قانونی جواز تسلیم کرنے کے بجائے مقتول کی دیت ادا کی گئی؟
★ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر یہودی عالم فنحاص کے پاس بیٹھے تھے کہ اس نے صدقہ اور زکوٰۃ کے حکم کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہمارا محتاج ہے جبکہ ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ سیدنا ابوبکر نے غصے میں آ کر فنحاص کے چہرے پر زور سے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اگر ہمارے اور تمھارے مابین معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورۂ آل عمران، آیت ۱۸۱)
عرفہ بن حارث کندی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نصرانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تو عرفہ نے زور سے مکہ مار کر اس کی ناک توڑ دی۔ معاملہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انھوں نے عرفہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ عرفہ نے کہا کہ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم نے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کی اجازت دینے پر معاہدہ کیا ہو۔ (بیہقی، السنن الکبریٰ، ۱۸۴۹۰۔ طبرانی، المعجم الکبیر ۱۸/۲۶۱)
سوال یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں کے خلاف عملی اقدام میں کسی قانونی اور فقہی نکتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ’ہر چہ بادا باد‘ کا رویہ ہی غیرت ایمانی کا معیار ہے تو سب وشتم کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے میں معاہدے کو مانع تصو رکرنے والے ان جلیل القدر صحابہ کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عقیدت ومحبت اور دینی غیرت وحمیت کا درجہ کیا متعین کیا جائے گا؟
حقیقت یہ ہے کہ توہین رسالت کا مسئلہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اتنا نازک ہے کہ اسے محض جذباتی زاویے سے دیکھنا کسی بھی اعتبار سے شرعی حکمتوں اور مصلحتوں کے قرین نہیں۔ اسلام کی دعوت، مسلمان معاشرے کی داخلی تشکیل اور اس کی دینی واخلاقی ساکھ اور دین وملت کے اجتماعی مصالح سے اس مسئلے کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ جذبات کی سطح پر مسلمان اس پر جو بھی رد عمل اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں، قانون اور سیاسی پالیسی کی سطح پر اس معاملے میں بہرحال حکیمانہ طرز عمل ہی اختیار کرنا ناگزیر ہے، اس لیے کہ قانون اور سیاست، دونوں کی اپنی عملی تحدیدات، ضروریات اور تقاضے ہیں جنھیں کم سے کم امت کے اہل علم ودانش اور فقہا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ علامہ قاسم بن قطلوبغا نے اسی نکتے کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ سب وشتم کے مسئلے میں ایک مسلمان کا دل اسی طرف میلان محسوس کرتا ہے کہ مجرم کو قتل کر دیا جائے، لیکن ہمارے لیے حنفی مذہب کی پیروی واجب ہے۔ بعض لوگ ان کی اس بات کو فقہی تعصب کی مثال کے طو رپر پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا درست محل یہ ہے کہ حنفی نقطہ نظر چونکہ قانون کی سطح پر شارع کے منشا کی زیادہ درست ترجمانی کرتا اور قانونی سوالات ومشکلات کا زیادہ قابل عمل جواب فراہم کرتا ہے، اس لیے جذباتی سطح پر ایک مسلمان کے احساسات کچھ بھی ہوں، تعبیر قانون کے دائرے میں اسی راے کی پابندی لازم ہے۔
مغربی مفادات کی تائید
اب اس ضمن کے آخری اعتراض کا جائزہ لیجیے:
اس میں شبہ نہیں کہ اہل مغرب اور ہمارے ہاں ان کے انداز فکر سے متاثر سیکولر حلقے، جو ملک کے سیاسی اور قانونی ڈھانچے کو مغربی طرز پر استوار دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اپنے مخصوص تصورات کے تحت پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے عمل سے ناخوش ہیں اور ان کی طرف سے ان قوانین کے خاتمے کے لیے مسلسل دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ جہاں تک سیکولر حلقوں کے اس نقطہ نظر کا تعلق ہے کہ ملک کے اجتماعی معاملات میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ توہین رسالت پر سزا جیسے قوانین چونکہ ریاست اور قانون کے اس مذہبی تشخص کو مستحکم کرتے ہیں، اس لیے ان کو کتاب قانون سے مٹا دینا چاہیے تو ہم اپنی اصل تحریر میں دوٹوک الفاظ میں واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان جیسے مسلم اکثریتی معاشرے میں اس نقطہ نظر کو کسی حال میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے لکھا ہے:
’’ممکن ہے اہل مغرب اپنے سیکولر زاویہ نگاہ کے تحت یہ مطالبہ کرنے میں اپنے آپ کو فی الواقع حق بجانب سمجھتے ہوں کہ کوئی ریاست قانونی دائرے میں مذہبی شعائر اور شخصیات کے ساتھ کسی وابستگی کا اظہار نہ کرے، لیکن ایک اسلامی ریاست کے لیے ایسے کسی مطالبے کو تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں جو ریاست کے مذہبی تشخص کے حوالے سے اسلام کی واضح ہدایات کو پامال کرتا ہو۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ مذہب کو صرف انفرادی معاملات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کو سماجی، قانونی اور سیاسی، ہر سطح پر اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو خدا اور اس کے رسولوں کے ساتھ اعتقادی وجذباتی وابستگی اور ان کی حرمت وناموس کی حفاظت محض ایک مسلمان کے انفرادی ایمان واعتقاد کا مسئلہ نہیں، بلکہ نظم اجتماعی کی سطح پر مسلمانوں کے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے اور جو چیزیں اسلامی ریاست کو ایک مخصوص نظریاتی تشخص اور امتیاز عطا کرتی ہیں، ان میں اسلامی حدود وشعائر کا تحفظ اور ان کی بے حرمتی کا سدباب بھی شامل ہے۔ چنانچہ یہ بات اسلامی ریاست کا ایک بنیادی فریضہ قرار پاتی ہے کہ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی حرمت وناموس اور مسلمانوں کی مذہبی غیرت وحمیت کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے پوری طرح چوکنا رہے اور قانون کی سطح پر اس نوعیت کے اقدامات کے سدباب کا پورا پورا اہتمام کرے۔ ‘‘
ہم نے توہین رسالت کے مسئلے کے حوالے سے جو کچھ عرض کیا ہے، اس کا بنیادی نکتہ سیکولر حلقوں کے مذکورہ زاویہ نظر کی تائید نہیں، بلکہ اس جرم کی شرعی سزا کے حوالے سے مختلف فقہی نقطہ ہائے نظر کی شرح ووضاحت اور ان میں سے احناف کے نقطہ نظر کی علمی ترجیح کو واضح کرنا ہے جو توہین رسالت کے مجرم پر پہلے ہی مرحلے میں سزاے موت نافذ کرنے کے بجائے اسے توبہ واصلاح کا موقع دینے اور عام حالات میں موت سے کم تر تعزیری سزا دینے کے قائل ہیں۔ اس تناظر میں ناقدین کا یہ اعتراض کہ ہماری اٹھائی ہوئی بحث مغربی زاویہ نظر یا مفاد کی تائید کرتی ہے، ایک بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے، یعنی یہ کہ اسلامی قانون کی تعبیر وتشریح کے حوالے سے مختلف نقطہ ہاے نظر پر غور وخوض اور علمی بحث ومباحثہ میں فیصلہ کن حیثیت مسلمانوں کی علمی وفقہی روایت کے داخلی اصولوں اور ضروریات وترجیحات کو حاصل ہے یا مغرب کے مطالبات کے جواب میں ایک مصنوعی طور پر فرض کیے گئے ’’متفقہ موقف‘‘ کے اظہار کو؟ دوسرے لفظوں میں اگر فقہ وشریعت کے داخلی اصولوں اور دلائل کی روشنی میں یہ واضح ہو جائے کہ کسی مخصوص مجرم کو ایک محدود دائرے میں رعایت دینا شارع کا منشا ہے یا کم از کم شارع کے منشا کے خلاف نہیں ہے تو آیا اس پہلو کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ اہل مغرب اس جرم پر سرے سے سزا ہی کو ختم کر دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟
اس طرز فکر کے مضمرات کو ایک مثال سے واضح کرنا مناسب ہوگا۔
قرآن مجید نے قتل عمد کی صورت میں قصاص کو فرض قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ مقتول کے ورثا کی طرف سے دیت پر رضامند ہو جانے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ قاتل کے لیے معافی کی گنجائش ہے، بلکہ اس نے خود ورثا کو ترغیب دی ہے کہ وہ عفو ودرگزر سے کام لیتے ہوئے دیت قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف قانونی اور تکنیکی وجوہ کے تحت قاتل کے لیے رعایت کی بہت سی صورتیں کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ یہی معاملہ چور کے لیے قطع ید اور شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا کا ہے اور فقہ اسلامی میں ایسے مجرموں کو مختلف صورتوں میں قطع ید اور رجم کی سزا سے مستثنیٰ قرار دے کر کم تر تعزیری سزا دینے کی رعایت نہ صرف ثابت ہے بلکہ ایسی رعایت تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
اسلامی شریعت کے ان تمام احکام پر اس وقت اہل مغرب کو اعتراض ہے۔ مغربی قانونی فکر نہ صرف یہ کہ ہاتھ کاٹنے اور سنگ سار کرنے کو سنگ دلانہ اور وحشیانہ سزائیں قرار دیتی ہے، بلکہ بڑی حد تک کسی بھی جرم پر سزاے موت دینے کو سرے سے ناجائز تصور کرتی ہے اور اہل مغرب کی طرف سے مسلمان معاشروں سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں ان سزاؤں کو کتاب قانون سے خارج کر دیں۔ اب زیر بحث طرز فکر کی رو سے اہل مغرب کے اس مطالبے کا جواب یہ بنتا ہے کہ چونکہ اہل مغرب قطع ید اور موت کی سزا کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس لیے ہم قاتل اور شادی شدہ زانی پر ہر حال میں سزاے موت جبکہ چوری کے مجرم پر ہر صورت میں قطع ید کی سزا نافذ کریں گے اور فقہ وشریعت کی روشنی میں ان مجرموں کو رعایت دینے کی کتنی ہی گنجائش کیوں نہ ہو، اہل مغرب کے سامنے ایک بے لچک موقف اختیار کرنے کے شوق میں ہم کسی مجرم کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔
بریں عقل ودانش بباید گریست
واقعہ یہ ہے کہ مذہبی حلقوں کا یہ جذباتی اور سطحی انداز فکر اسلامی قانون سازی کے عمل کو تقویت پہنچانے اور اسے آگے بڑھانے کے بجائے الٹا اسے نقصان پہنچانے کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ اسلامی قانون سازی کے مخالف حلقوں کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں استدلال کے طور پر جہاں اصولی اور نظریاتی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، وہاں موجودہ قوانین میں پائے جانے والے بعض نقائص اور خامیاں اور قوانین کے غلط استعمال کی مثالیں بھی ایک کارآمد ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نوعیت کے اعتراضات کے حوالے سے مذہبی حلقوں کا رویہ نہ صرف یہ کہ سنجیدہ نہیں بلکہ غیر حکیمانہ بھی ہے جس سے نہ صرف ان قوانین کے متعلق بلکہ مذہبی جماعتوں کے متعلق بھی منفی تاثرات جنم لیتے ہیں۔
یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ ملک میں جو اسلامی قوانین نافذ ہیں، وہ بہرحال انسانی کاوش ہیں اور ان میں نہ صرف تعبیر قانون کے زاویے سے بلکہ عملی تجربات کے لحاظ سے بھی نقائص رہ جانے کا پورا امکان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ شرعی وفقہی اصولوں اور عملی تجربات کی روشنی میں ان کا مسلسل جائزہ لیتے رہنے اور انھیں بہتر سے بہتر بنانے کی گنجائش بلکہ ضرورت بھی پوری طرح موجود ہے۔ تاہم عملاً یہ ہو رہا ہے کہ مذہبی حلقے اسلامی قوانین کے نفاذ کے بعد اس پہلو سے بالکل صرف نظر کرتے چلے آ رہے ہیں جبکہ ان قوانین کے حوالے سے پیدا ہونے والے عملی مسائل کو اجاگر کرنے اور پھر انھیں اسلامائزیشن کے پورے عمل کے خلاف پراپیگنڈا کے لیے استعمال کرنے کی ذمہ داری سیکولر طبقات نے سنبھال رکھی ہے۔ مذہبی طبقات اس سارے عمل میں صرف اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب کسی قانون کے ضمن میں کوئی عملی اقدام کیا جانے لگتا ہے اور چونکہ میدان اصلاً مخالف عناصر نے سجایا ہوتا ہے، اس لیے کئی مواقع پر غیر جانب دارانہ نظر سے صورت حال کا مشاہدہ کرنے والے کو صاف محسوس ہوتا ہے کہ مذہبی حلقے اپنی دفاعی پوزیشن کی کمزوری کو اقدامی طاقت میں بدلنے کے لیے عوامی جذبات اور رائے عامہ کی طاقت کا سہارا لینے کی حکمت عملی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بظاہر متعلقہ قوانین کو ’’بچانے‘‘ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن قانون کے حوالے سے جو واقعی نظری یا عملی سوالات موجود ہوتے ہیں، وہ جوں کا توں باقی رہتے ہیں۔
جنرل پرویز مشرف کے دور میں حدود قوانین میں ترمیم کی ضرورت کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں بحث ومباحثہ کا میدان سجایا گیا تو مذہبی حلقوں نے ابتدا میں سارا زور یہ ثابت کرنے پر صرف کیا کہ یہ قوانین اعلیٰ سطحی اسلامی ماہرین نے بہت گہرے غور وفکر اور مشاورت کے بعد بنائے ہیں اور ان میں جو خلا یا نقائص بتائے جاتے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں، اس لیے ان میں کسی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم آخرکار خود علما کی ایک کمیٹی نے ان میں سے بعض قوانین کو شرعی لحاظ سے قابل اصلاح تسلیم کرتے ہوئے خود ان میں ترمیم کے لیے تجاویز پیش کیں۔ اس سارے عمل سے ذہنوں میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوا کہ اگر قانون میں یہ خامیاں موجود تھیں تو گزشتہ تیس سال میں مذہبی حلقوں نے ان کی اصلاح کے لیے کوشش کیوں نہیں کی اور ہر موقع پر یہ اصرار کیوں کیا جاتا رہا کہ ان قوانین کو چھیڑنا حدود اللہ اور احکام شرعیہ میں مداخلت کے ہم معنی ہے؟ دوسرا تاثر یہ پیدا ہوا کہ مذہبی طبقات کا رویہ شرعی قانون سازی کے حوالے سے خالص علمی اور شرعی وفقہی بنیادوں کے بجائے سیاسی مصلحتوں اور مفادات پر استوار ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی کوششوں سے کوئی ایسا قانون بن گیا ہے جو شرعاً قابل اصلاح ہے تو بھی اس کی اصلاح وترمیم کے ضمن میں کسی دوسرے فرد یا حلقے کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں اور یہ حق بلاشرکت غیرے مذہبی حلقوں ہی کے لیے خاص ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے شرعی قانون سازی کا سارا عمل بنیادی طو رپر ایک سیاسی اور طبقاتی کشمکش کا رنگ اختیار کر کے اپنی اخلاقی اور دینی ساکھ سے محروم ہو جاتا ہے۔
شرعی قوانین اور بالخصوص توہین رسالت کے قانون کے غلط اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی بات بھی نہایت توجہ کے قابل ہے اور اگرچہ الزامی طور پر یہ بات کہہ دینے کی گنجائش موجود ہے کہ غلط استعمال تو ہر قانون کا ہو رہا ہے، تاہم مذہبی طبقات کی طرف سے مثبت طور پر اس کی روک تھام کے لیے جس قدر کوشش کی ضرورت ہے، اس کی ادنیٰ خواہش بھی ان کے ہاں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے نتیجے میں غیر مسلم اقلیتیں، جو اصولی طورپر توہین رسالت پر سخت سزا کے قانون کے خلاف نہیں اور ان کے اعلیٰ سطحی ذمہ دار راہ نما اپنا یہ موقف برملا ظاہر کر چکے ہیں، جب کسی مشکل سے دوچار ہوتی ہیں تو انھیں اپنے حق میں آواز اٹھانے کے لیے مذہبی راہ نما اور علما نہیں، بلکہ غیر مذہبی قائدین ہی میسر آتے ہیں۔ مظلوم غیر مسلموں کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، اگر خود مسلمانوں کے مذہبی فرقوں کے مابین کہیں تصادم ہو جائے تو کسی بھی فریق کے ذمہ دار قائدین اور اعلیٰ سطحی راہ نماؤں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حلقے کے اختیار کردہ طرز عمل کے بارے میں تحفظات یا اعتراضات رکھتے ہوئے بھی عوامی جذبات سے مختلف کوئی بات علانیہ کہہ سکیں۔ اس ضمن میں ان کی عملی مجبوریوں سے انکار نہیں، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ مذہبی قیادت کو درپیش اس داخلی مشکل سے مسیحی راہ نماؤں کے اس سوال کا کوئی جواب بہرحال فراہم نہیں ہوتا کہ اگر مسلمانوں کے مذہبی راہ نما خود اپنے پیروکاروں کے طرز عمل کو حدود کا پابند رکھنے کی عملی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو وہ مسیحی اقلیت سے یہ مطالبہ کس منہ سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سیکولر لابیوں کی مہم کو تقویت پہنچانے کے بجائے اپنا وزن اسلام پسندوں کے پلڑے میں ڈال دیں؟
ہماری رائے میں یہ صورت حال اس بات کی متقاضی ہے کہ ملک وملت کے اجتماعی معاملات میں عملی کردار ادا کرنے والے مذہبی طبقات محض جذباتیت کو فروغ دینے اور اس کے سہارے وقتی نوعیت کے سیاسی اقدامات کرنے کے بجائے اپنی دینی واخلاقی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی کا راستہ اختیار کریں اور مذہب اور اہل مذہب کے اجتماعی کردار کو مفید، مثبت اور موثر بنانے کے لیے اپنی موجودہ حکمت عملی کا گہرا ناقدانہ جائزہ لے کر اس کی اصلاح کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔ ہمارے نزدیک اس ضمن میں حسب ذیل اقدامات ناگزیر ہیں:
۱۔ ملک میں نافذ اسلامی قوانین کے حوالے سے علمی وفقہی سطح پر یا عملی تجربات کی روشنی میں جو مختلف توجہ طلب سوالات سامنے آتے رہتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے لیے تمام دینی جماعتوں کے نمائندہ علما پر مشتمل ایک مستقل کمیٹی قائم کر دی جائے جو اس طرح کے مسائل پر تسلسل کے ساتھ غور وفکر کرتی رہے۔ مذہبی جماعتیں اس کمیٹی کے پیش کردہ تجزیوں کی روشنی میں، مخالف عناصر کی طرف سے کسی مہم کا انتظار کرنے کے بجائے، ازخود اصلاح طلب پہلووں کے بارے میں ذمہ دارانہ موقف اختیار کریں اور آئینی وقانونی اداروں کی سطح پر مطلوبہ تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
۲۔ توہین رسالت سے متعلق حالیہ قانون چند بنیادی اور اہم پہلووں سے نظر ثانی کا محتاج ہے، اس لیے جید اور ذمہ دار علما کی راہ نمائی میں مذہبی جماعتیں درج ذیل امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ترمیم شدہ اور جامع مسودۂ قانون پارلیمنٹ میں پیش کریں:
الف۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہریت کے لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے احترام کو بنیادی شرط قرار دیا جائے اور کوئی بھی شخص جو اپنے قول وفعل سے اس شرط کی دانستہ خلاف ورزی کرے، اس کے حقوق شہریت منسوخ کر دیے جائیں۔
ب۔ توہین رسالت کا جرم کسی ایک فرد کے خلاف نہیں، بلکہ پورے مسلمان معاشرے اور ریاست کے خلاف جرم ہے، اس لیے اس میں قانونی طو رپر مدعی بھی کسی فرد کو نہیں، بلکہ ریاست کو ہونا چاہیے، جبکہ عام لوگوں کا کردار ایسے کسی بھی معاملے کو محض قانون کے نوٹس میں لانے تک محدود ہونا چاہیے۔
ج۔ مجرم سے پہلی مرتبہ جرم سرزد ہوا ہو تو اسے توبہ، معذرت اور معافی کا موقع دیا جائے، البتہ جرم کے مکرر ارتکاب کی صورت میں قرائن وشواہد سے یہ واضح ہو جائے کہ مجرم صرف دفع الوقتی کے لیے معذرت کا سہارا لے رہا ہے جبکہ حقیقی طور پر اپنے رویے کی اصلاح پر آمادہ نہیں تو اس کی توبہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے۔
د۔ جرم کی نوعیت اور اثرات کے لحاظ سے سزاے موت کے ساتھ ساتھ متبادل اور کم تر سزاؤں کی گنجائش بھی قانون میں شامل کی جائے، جبکہ موت کی سزا کو اس جرم کی انتہائی سزا قرار دیتے ہوئے اسی صورت میں نافذ کیا جائے جب جرم کے سد باب اور اس کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لیے یہی سزا ناگزیر ہو۔
ہ۔ اگر توہین رسالت کا الزام جھوٹا ثابت ہو تو الزام لگانے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ شخصی اور گروہی وطبقاتی نزاعات میں اس الزام کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔
۳۔ ہر شہر میں تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار علما اور مقامی طور پر بااثر سماجی وسیاسی شخصیات پر مشتمل ایک مستقل کمیٹی قائم کی جائے جو کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم کے خلاف توہین رسالت کا الزام سامنے آنے کی صورت میں اپنے اجتماعی اثر ورسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی گروہ عوامی جذبات کو بھڑکا کر انھیں قانون کو ہاتھ میں لینے یا پولیس اور عدالت پر دباؤ ڈال کر ان کی جانب داری کو مشکوک بنانے کی کوشش نہ کر سکے۔*
ہذا ما عندی والعلم عند اللہ۔
حواشی
* اس کی ایک اچھی مثال حال ہی میں گوجرانوالہ میں پیش آنے والے ایک واقعے میں سامنے آئی۔ کھوکھرکی کے علاقے میں، جہاں مسیحی لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں، قرآن مجید کے اوراق جلائے جانے کے الزام میں کچھ مسیحیوں کا نام لے کر ان کے خلاف احتجاجی جلوس منظم کیے گئے جس پر علاقے کی مسیحی آبادی میں خوف وہراس پھیل گیا اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے مکانات چھوڑ کر چلے گئے۔ تاہم شہری انتظامیہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ الزام غلط ہے اور ملزموں کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ضمن میں شہر کے تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار علما کی میٹنگ طلب کر کے انھیں صورت حال سے آگاہ کیا گیا تو علما نے کم وبیش اتفاق رائے سے اس حرکت کی مذمت کی اور انتظامیہ پر زور دیا کہ جب الزام کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا ہے تو بے گناہ مسیحیوں کو تنگ نہ کیا جائے اور اس کے بجائے اصل ذمہ داروں کو تلاش کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔
دھڑکٹی تصویر اور فقہِ حنفی
مولانا محمد عبد اللہ شارق
اگر کسی مسئلہ یاواقعہ کے شرعی حکم کے بارہ میں فقہا کا کوئی ایک نکتۂ نظر مشہور ہوجائے توضروری نہیں ہوتا کہ فی الواقع بھی اس مسئلہ میں اہل علم کا صرف ایک ہی نکتۂ نظر ہو اور وہ سب اس ایک رائے پر متفق ہوں جو اس مسئلہ کے شرعی حکم کے حوالہ سے زبان زدِ عام ہوچکی ہے ۔ ایسے درجنوں مسائل کی نشان دہی کی جاسکتی ہے جن کے بارہ میں عوام تو عوام، اچھے بھلے سنجیدہ اور فہمیدہ لوگ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ یہ اختلاف سے ماورا، اجماعی اور متفقہ ومنصوص مسائل ہیں حالانکہ درحقیقت ان کے اندر اہلِ علم کی ایک سے زیادہ آراء موجود ہوتی ہیں۔ ہماری مراد اس سے وہ مسائل نہیں ہیں جن کے اندر کسی زمانہ میں علماءِ امت کا اختلاف تھا اور بعد میں اللہ کی کسی تکوینی حکمت کے تحت یا کسی ایک موقف کی قطعیت سامنے آنے کے بعد پوری امت ان کے اندر یک رائے ہوگئی، جسے اصولِ فقہ کے اندر ’’اجماع من بعد الصحابۃ علی قول سبقہم فیہ مخالف‘‘ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے (۱)کیونکہ یہ اتفاق بھی کسی نہ کسی درجہ میں بہرحال اجماع کے دائرہ میں ہی آتا ہے ۔ ہمارا اِشارہ یہاں اُن ’’مظلوم مسائل‘‘ کی طرف ہے جو کبھی بھی اجماعی نہیں رہے ،مگر ان کے اندر کسی ایک مکتبِ فکر کا نکتۂ نظر اس حد تک مشہور ہوا کہ علماء کی نظروں سے بھی اس مسئلہ کے اندر موجود ایک دوسرا نکتۂ نظراوجھل ہوگیااور اسی شہرت کے زیرِ اثر غلط طور پر یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ اجماعی مسائل ہیں۔اگر اجماع وقطعیت کا یہ دعوی کسی ایک دور کے علماء کی ذاتی تحقیق اور ان کے ذاتی اتفاقِ رائے کی حدتک ہوتا تو درست اور قابلِ فہم تھا،لیکن چونکہ سرے سے یہ دعوی کسی تحقیق یازمینی حقائق پر مبنی ہی نہیں تھا اِس لیے کم علمی کی وجہ سے اس اتفاق کو ماضی وحال کی تمام وسعتوں تک محیط کردیا گیااور اس میں اُن اصحابِ نظر کو بھی شامل کرلیا گیا جنہوں نے واشگاف الفاظ میں اس مسئلہ کے اندر اپنے اختلافی نکتۂ نظر کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ ہواکہ جب کوئی طالبِ علم جھاڑ پونچھ کر پرانے اکابرین میں سے ہی کسی مقتدر شخصیت کا اس مسئلہ میں اختلافی نکتۂ نظر میدان میں لے کر آیا تو اچھے اچھے صاحبانِ علم نے اس پر حیرت کے مارے انگلیاں منہ میں دبا لیں۔
ان مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے جن پر ہم تفصیل سے گفتگو کسی موقع پر کریں گے ۔فی الحال ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے، وہ تصویر کی حرمت کا ہے ۔یہ بھی انہی ’’مظلوم مسائل‘‘ میں سے ایک ہے ۔ یہ درست ہے کہ تصویر کی حرمت چودہ صدیوں میں امت کے ہاں اجماعی اور غیرمختلف فیہ رہی ہے ،لیکن یہ اجماع تصویر کے مجمل شرعی حکم کی حد تک ہے۔ ذیلی جزئیات و تفصیلات سے اِس کا کوئی تعلق نہیں،جیساکہ نماز کی فرضیت ، اذان کی مشروعیت اور ربا کی حرمت بھی فقہاءِ امت کے مابین اتفاقی امور ہیں ، لیکن یہ اتفاق ان کے فی الجملہ شرعی حکم تک محدود ہے ۔سب جانتے ہیں کہ ضمنی تشریحات اور اجتہادی صورتوں کے ساتھ اِس اتفاق کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر اجماعی مسائل میں اجماع اور اتفاق کا پھیلاؤ بس اِ سی قدر ہی ہوتا ہے،فقہی تفریعات اور اصولی موشگافیاں عموماً اس کے دائرہ سے باہر ہی ہوتی ہیں۔مسئلہ تصویر کی تفصیلات میں صرف ائمہ اربعہ کی مختلف آرا کا اجمالی مطالعہ کرنے کے لیے کتاب الفقہ علی المذاہب الأربعۃ کو دیکھا جاسکتا ہے ۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ کلاسیکی فقہا میں سے صرف ائمہ اربعہ کا اس مسئلہ میں کتنا اختلاف ہے اور یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ حرمت تصویر کے اجماعی فتوی کے باوصف کتنی ہی قسم کی تصاویر اس فتویٰ سے مستثنیٰ ہیں ؟
ہماری کھود کرید او رجانچ پڑتال کے مطابق جو تصاویر اِ س فتوی سے مستثنی ہیں اور چاروں مذاہب میں بالاتفاق ان کے جواز کی گنجائش موجود ہے ، ان میں جان داروں کی سربریدہ تصاویر یاجسم کے صرف اتنے حصے کی تصاویر شامل ہیں جس کے ساتھ اس جان دار کا زندہ اور بقیدِ حیات رہنا ممکن نہیں ہوتا۔شیخ عبدالرحمن الجزیریؒ احناف کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :’’الحنفیۃ قالوا : ۔۔۔وکذلک یجوز اذاکانت الصورۃ ناقصۃ عضوالایمکن ان تعیش بدونہ کالرأس ونحوہ‘‘(۲) مالکیہ کا مذہب بیان کرتے ہیں:’’المالکیۃ قالوا: انما یحرم التصویر بشروط اربعۃ ۔۔۔ثالثہا : ان تکون کاملۃ الاعضاء الظاہرۃ التی لایمکن ان یعیش الحیوان او الانسان بدونہا، فان ثقبت بطنہا اورأسہا او نحو ذلک فانہا لاتحرم‘‘ (۳) شوافع کے بارہ میں لکھتے ہیں: ’’الشافعیۃ قالوا:۔۔۔وان کان مجسدا فانہ یحل التفرج علیہ اذا کان علی ہیءۃ لایعیش بہا کأن کان مقطوع الرأس أوالوسط أوببطنہ ثقب‘‘ (۴) نیز حنابلہ کا موقف نقل کرتے ہیں:’’الحنابلۃ قالوا:۔۔۔ فاذاکان مجسدا ولکن ازیل منہ مالاتبقی معہ الحیاۃ کالرأس ونحوہا فانہ مباح‘‘ (۵) ان عبارات سے ظاہر ہورہا ہے کہ مذاہبِ اربعہ میں جان داروں کی ایسی نامکمل تصاویر کی گنجائش موجود ہے جو بغیر سر کے ہیں یا کسی اور ایسے عضو کے بغیر ہیں جس کے بغیر اس جان دار کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔
چونکہ ہماری گفتگو کا خاص موضوع اِس وقت فقہِ حنفی ہے ، اس لیے ہم فقہِ حنفی کی نصوص کے حوالہ سے ہی اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہیں۔احناف کے نزدیک تصویر کی کراہت کا ایک دائرہ اس کے عمومی استعمال کا ہے جبکہ دوسرا دائرہ نمازی کے قریب موجود ہونے کا ہے۔اِن دونوں دائروں کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات ہیں اور دونوں میں علتِ کراہت بھی مختلف ہے ۔ علامہ ابنِ عابدینؒ لکھتے ہیں :’’علۃ حرمۃ التصویر المضاہاۃ لخلق اللہ ۔۔۔وعلۃ کراہۃ الصلوۃ بہا التشبہ‘‘ (۶) عمومی استعمال کے باب میں حرمتِ تصویر کی علت المضاہاۃ لخلق اللہ یعنی اللہ کی تخلیق کے ساتھ تشابہ ،اس کی نقالی اور یک گونہ مقابلہ بازی ہے ۔ یہ علت درج ذیل حدیث کے مضمون سے اخذ کی گئی ہے :’’ان اصحاب ہذہ الصور یعذبون یوم القیمۃ ، یقال لہم : احیوا ما خلقتم‘‘ (۷) نیز فرمایا: ’’من صور صورۃ فی الدنیا کلف یوم القیمۃ ان ینفخ فیہا الروح، ولیس بنافخ‘‘ (۸) ان احادیث میں تصویر سازی کی اخروی سزا بیان کی گئی ہے کہ مصور کو روزِ قیامت اپنی تصاویر میں روح ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا جوکہ اس کے بس میں نہیں ہوگااور اس کی وجہ سے وہ بے بسی اور اضطرار کی جس تکلیف دہ اندرونی کیفیت سے دوچار ہوگا ، وہی اس کی سزا ہوگی۔ حدیث کا مضمون واضح طور پر بتارہا ہے کہ تصویر سازی صرف جان داروں کی ہی حرام ہے کیونکہ بے جان اشیا میں روح ڈالنے کے حکم کا کوئی معنی نہیں ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ خود احادیث وآثار سے ہی بے روح اشیا کی تصویر سازی اور عکاسی کا جواز صراحتاً ثابت ہے اور نیز یہی وجہ ہے کہ چونکہ جان دارکی صورت گری ہی حرام ہے اس لیے بغیر سر کے کسی جان دار کی تصویر بنانا بھی حرام نہیں ہے کیونکہ بغیر سر کے کوئی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتا اور اِس صورت میں وہ تصویر گویا کسی بے جان اور جامد چیز کی ہوگی جس میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے ۔
اس تفصیل کی روشنی میں احناف کے نزدیک المضاہاۃ لخلق اللہ کی علت کا معنی ومفہوم اور حدودِ اربعہ بھی پور ی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ یہ علت کامل طور پر اسی صورت میں متحقق ہوگی کہ جب تصویر ذی روح کی ہو ا ور اس میں ان تمام ظاہری اعضا کی ضرور عکاسی کی گئی ہو جو اس کے وجود کے لیے لابدی اور مالایعیش بدونہ کے درجہ میں ہیں۔مطلق مضاہات علتِ ممانعت نہیں۔چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی ؒ مقطوع الرأس تصویر کے جواز کے حق میں احادیث وآثار نقل کرنے کے بعد یہی نتیجہ اخذکرتے ہوئے فرماتے ہیں: ’’فلما ابیحت التماثیل بعد قطع رؤسہا الدی لو قطع من ذی الروح لم یبق دل ذلک علی اباحۃ تصویر مالاروح لہ وعلی خروج مالاروح لمثلہ من الصور‘‘ (۹)۔ (حافظ ابنِ حجر عسقلانی ؒ نے بھی بعض علما کی طرف اِس استدلال کو منسوب کرنے کے بعدسنن نسائی کی ایک حدیث کی روشنی میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ (۱۰) امام طحاوی ؒ کا یہی مدققانہ استدلال بعد میں فقہاءِ احناف کے مقطوع الرأس کے ساتھ ساتھ مقطوع عضوٍ لایعیش بدونہ کو بھی مستقل طور پر مباح تصاویر کی فہرست میں شامل کرنے کا سبب بنا۔ علاؤالدین الحصکفی ؒ لکھتے ہیں: ’’ولایکرہ لو کانت ۔۔۔أو مقطوعۃ الرأس أوا لوجہ أو ممحوۃ عضوٍ لاتعیش بدونہ (۱۱) نیز شیخ احمد الطحطاوی ؒ لکھتے ہیں: ’’قطع الرأس لیس بقید، بل المراد جعلہا علی حالۃ لاتعیش معہا مطلقا‘‘ (۱۲) مؤخر الذکر دونوں عبارات ’’مکروہات الصلوۃ‘‘ کے باب سے نقل کی گئی ہیں جس سے یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ اِن تصاویر کی عدمِ کراہت کا تعلق محض نماز کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ۔ جس طرح مقطوع الرأس تصویرعدمِ مضاہات کی وجہ سے عمومی استعمال کے لیے بلاکراہت جائز ہے ، مقطوع مالایعیش بدونہ کے اندر بھی بعینہ اسی طرح مضاہات کی علت مفقود ہے،اس لیے اس کی عدمِ کراہت کو بھی محض نماز کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔
البتہ سرکٹی تصویر کی طرح نہ تو ہم دھڑکٹی تصویر (جس کی ضرورت آج قدم قدم پر مختلف امورِدنیامیں پیش آتی ہے اور جو اس وقت ہماری تحقیق کا اصل موضوع ہے ) کو قطعی طور پر جائز سمجھتے ہیں اور نہ ہی اہل علم سے اس کو بہر صورت جائز سمجھنے کا تقاضاکرتے ہیں کیونکہ یہ ایک اجتہادی تخریج ہے ،کوئی منصوص مسئلہ نہیں ۔اس لیے اس میں خطا و صواب کا امکان برابر موجود ہے او راہل تحقیق کو اِس میں کراہت یا عدمِ کراہت کا کوئی ایک نکتۂ نظر اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ ماضی میں بھی ہمارے حنفی فقہاء ہی کے مابین اِ س تصویر کا جواز کوئی متفق علیہ امر نہیں رہا۔ فتاویٰ عالم گیری کی عبارت ملاحظہ فرمائیں: ’’اختلف المشائخ فی رأس الصورۃ بلاجثۃ ہل یکرہ اتخاذہ والصلوۃ عندہ؟‘‘ (۱۳) نیز علامہ شامی لکھتے ہیں: ’’قال القہستانی : فیہ اشعاربأنہ لاتکرہ صورۃ الرأس وفیہ خلاف کما فی اتخاذہا،کذا فی المحیط‘‘ (۱۴) پاک وہند کے علماء میں اگرچہ جواز کے قول کو زیادہ پذیرائی حاصل نہیں رہی، مگر ثقہ علما نے ہمیشہ جواز کے ایک قول کا بہرحال اعتراف ضرور کیا ہے اور اِس تصویر کو متفقہ طورپر حرام کبھی نہیں کہا ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ امدادالفتاوی میں ردالمحتار کی ہی مذکور الصدر عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :’’اس سے معلو م ہوا کہ اس میں بوجہ اختلاف کے ضرورت والے کو گنجائش ہے، گو غیر ضرورت والے کو بقاعدہ اذا تعارض المحرم والمبیح الخ منع کو ترجیح ہوگی۔‘‘ (۱۵)‘‘نیز مفتی محمد شفیع ؒ لکھتے ہیں :’’لیکن اگر ناقص تصویرمیں چہرہ موجود ہو تو خواہ بدن باقی نہ ہو توایسی تصویر کا استعمال اکثر فقہا کے نزدیک جائز نہیں ، مگر بعض حضراتِ حنفیہ اور اکثرمالکیہ اس کے استعمال کوبھی جائز فرماتے ہیں۔‘‘ (۱۶)
مولانا مفتی محمد شفیع ؒ نے عدمِ جواز کی ترجیح ثابت کرنے کے لیے جواز کے موقف پر کئی اشکالات بھی وارد کیے ہیں (۱۷)، جبکہ ان سے قبل مولانا احمد رضاخان بھی اِس نکتۂ نظر پر بہت تفصیل سے ناقدانہ کلام کرچکے ہیں۔(۱۸)اٹھائے گئے نکاتِ اعتراض میں سے ایک مشہور اعتراض یہ ہے کہ تصویر کے اندر اصل مقصود چہرہ ہوتا ہے ، اس لیے جب تک چہرہ باقی رہے گا ، اس وقت تک تصویر بھی باقی رہے گی اور حرمت کا حکم مرتفع نہیں ہوگا۔ یہ اعتراض بظاہر بہت معقول اور وزنی ہونے کے باوجود اپنی اصل میں بالکل قابلِ التفات نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کے اندر چہرہ کے ’’اصل مقصود‘‘ ہونے سے کیا مراد ہے ؟اگر یہی کہ لوگوں کے مقاصد اور ضروریات اسی قدر سے پورے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں یہ چیز ممانعت کی کوئی شرعی وجہ نہیں۔احناف کے نزدیک حرمت کی وجہ المضاہاۃ لخلق اللہ ہے ، نہ کہ عرفِ عام کے اندر اس کا قابلِ اعتبار اور بامقصد ہونا یا لوگوں کی معاشرتی ، قانونی اور حفاظتی ضروریات کے ایک خاص دائرہ میں اس کا کارآمد ہونا ، بلکہ فقہا کے کسی بھی مکتبِ فکر کے نزدیک تصویر کے عدمِ جواز کی یہ علت نہیں ۔نیز اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اِس صورت میں صرف دھڑکٹی تصویر کو ہی نہیں ، سرکٹی تصویر کو بھی ناجائز ہی کہنا پڑے گاکیونکہ جس طرح محض چہرہ کی تصویر بعض اوقات مقصودِ اصلی اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ، بعینہ اسی طرح بعض اوقات صرف نچلے دھڑ کی تصویر بھی اصل مقصود کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے ۔چہرہ کی تصویر اگر ایک فرد کا تعین کرتی ہے تو نچلے دھڑ کی تصویرجان داروں کی اصناف میں سے کسی ایک صنف کا تعین کرتی ہے ۔اگر مصور کا تخیل تصویر کے اندر جان داروں کی کسی خاص جنس کی عکاسی کا تقاضاکرتاہے تو وہ اس کے چہرہ کو مدہم یاکسی دوسری چیز کے اندر مدغم کرکے بھی اپنا کام چلاسکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا اصل مقصود چہرہ نہیں ، بلکہ نچلا دھڑ قرار پائے گا۔تو کیا ’’مقصود‘‘ ہونے کی وجہ سے اِس کو بھی ناجائز کہا حائے گا؟حالانکہ بغیر سر کے نچلے دھڑ کی تصویر اجماعاً مباح ہے ۔(۱۹)
مکررعرض ہے کہ ہمارا مقصود کسی ایک نکتۂ نظر کی ترجیح پر اصرار کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ازراہِ کرم مختلف فیہ مسائل کو اپنی کم علمی کی بھینٹ چڑھا کر اجماعی مت بنائیں۔ ایسا کرکے ہم دین کی کوئی خدمت سرانجام نہیں دے رہے ۔ محض چہرہ کی تصویر اگر بعض علماء کے نزدیک جائز ہے تو آپ بے شک اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں،مگر اس کے اندر موجود اختلاف کا بھی اعتراف کریں اور دوسروں کو اپنی رائے کا مکلف اور پابند بنانے کی بجائے،اختلاف کی وجہ سے اس مسئلہ میں جو شرعی گنجائش پیداہورہی ہے ،اپنے دیانت دارانہ موقف پر کاربندرہنے کے باوصف اختلاف الأمۃ رحمۃ اور الدین یسر کے تحت لوگوں کو اس سے مستفید ہونے دیں۔فقہِ حنفی میں کئی ایسی نظائر موجود ہیں کہ جن کے اندر مسئلہ کے شرعی حکم میں ہمارے فقہا نے صرف اس لیے تخفیف کردی کہ یہ مجتہدفیہ مسئلہ ہے اور اس میں بعض اہلِ علم کا اختلاف ہے (باوجو داس کے کہ ایک مجتہد صرف اپنے اجتہاد کا مکلف ہوتاہے ، کسی دوسرے کی رائے کے لحاظ اور رعایت کانہیں)مثال کے طور پر:
۱۔نجاستِ خفیفہ کے تصور کو لے لیں۔ امام محمد ؒ کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے جبکہ امام ابوحنیفہ ؒ اور امام ابویوسف ؒ کی تحقیقی رائے اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہ نجاست کے قبیل سے ہے ،لیکن وہ اسے ہلکی نجاست(نجاستِ خفیفہ ) کہتے ہیں۔ اس کی وجہ ؟ صرف یہ کہ اِس کی نجاست کا حکم منصوص اور قطعی نہیں،بلکہ مجتہدفیہ ہے ۔(۲۰)
۲۔’’عورتِ غلیظہ ‘‘،’’عورتِ متوسطہ‘‘ اور’’ عورتِ خفیفہ ‘‘کی درجہ بندی کو لے لیں۔ احناف کے نزدیک مرد کے جسم میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے ، مگر ان کے نزدیک گھٹنا معمولی ، ران متوسط اور اعضاءِ رئیسہ بڑے درجہ کی ’’برہنگی ‘‘ شمارہوتے ہیں۔ (۲۱)بعدازاں اس درجہ بندی کے اثرات فروعی احکام پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ میت کو غسل دیتے وقت غسال کی سہولت کے لیے صرف اس کے اعضاءِ رئیسہ (عورتِ غلیظہ ) کو چھپالینا ہی کافی ہے۔(۲۲)نیز اگر کسی آدمی کا ستر کھلا ہوا ہے تو اِن درجات اور مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ گھٹنا یا ران کے کھلے ہونے کی صورت میں زیادہ سختی سے پیش آنا جائز نہیں۔(۲۳)اس درجہ بندی کا پسِ منظر کیا ہے ؟کوئی آیت یا حدیث نہیں ، محض اس کی ’’مجتہد فیہ‘‘ کی حیثیت ہی ہے کیونکہ شوافع کے نزدیک گھٹنا ستر میں شامل نہیں ، جبکہ اصحابِ ظواہر کے نزدیک ران بھی اِس میں شامل نہیں۔ البتہ چونکہ اعضاءِ رئیسہ کے ستر ہونے پر اتفاق ہے اس لیے اس کو عورتِ غلیظہ قرار دیا گیا ہے ۔(۲۴)
۳۔اگر نفل نماز شروع کرکے توڑ دی جائے تو احناف کے نزدیک اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے ، لیکن بعض صورتیں احناف کے نزدیک بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں ۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے اندر اولاًً نفل نماز کے صحیح طور سے شروع ہونے میں اختلاف ہے ۔ احناف کے نزدیک اگرچہ تحریمہ صحیح ہوگیا تھا اور اس وجہ سے اِن صورتوں میں بھی ان کے نزدیک توڑے گئے دوگانہ کو واجب الاعادہ ہونا چاہئے تھا مگر فی الواقع ایسا نہیں۔ کیوں؟صرف اس لیے کہ اصلاً اس تحریمہ کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے ۔ اگر نماز اُسی تحریمہ سے مکمل کرلیتا تو احناف کے نزدیک مستحقِ اجر ہوتا ،لیکن اگر درمیان میں قطع کردی ہے توخلافِ قاعدہ اس کا اعادہ ضروری نہیں کیونکہ اُس تحریمہ کی صحت ’’مظنون‘‘ اور مجتہد فیہ ہے۔ (۲۵)
یہ تین مثالیں صرف ’’عبادات وقربات ‘‘ کے باب سے نقل کی گئی ہیں جس کے اندر بالاتفاق احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنا مطلوب ہے۔ اگر اس باب کے اندر اسلافِ امت اور خصوصاً ہمارے فقہاءِ احناف اپنے موقف پر کاربند رہتے ہوئے محض مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے اتنی آسانیاں فراہم کررہے ہیں تو معاشی ، معاشرتی اور سماجی نوعیت کے مسائل میں اس پہلو کو ملحوظ رکھنا کس حدتک ضروری ہوگا ؟بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔شاید اسی وجہ سے حضرت گنگوہی ؒ اور حضرت تھانویؒ سے معاملات کے باب میں لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے ائمہ اربعہ میں سے کسی بھی امام کے مذہب پر فتوی دینے کا جواز بلکہ پسندیدگی منقول ہے۔ (۲۶)
ہمارے خیال میں’’ الشریعہ ‘‘کے مکتوب نگار مولانا سختی داد خوستی کو ان طالب علمانہ گذارشات کی روشنی میں اپنے مکتوب کے ان مندرجات پر نظر ثانی کرلینی چاہیے جن کے اندر وہ تصویر کی حرمت کو پوری شدومد کے ساتھ متفق علیہ امر لکھ کر اکابرینِ وفاق سے اپنی اس نئی پالیسی کو تبدیل کرنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں جس کے تحت امتحان کے شرکا کو داخلہ فارم کے ساتھ پاسپورٹ سائز کی تصویر جمع کرانے کا پابند بنایا گیا ہے ۔ تاہم ان کا یہ شکوہ بجا ہے کہ ’’ہم لوگ ‘‘ کل تک جس امر کو پوری قطعیت کے ساتھ حرام کہتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات کا ذرا بھی اعتبار نہ کرتے ہوئے ان کے لیے اسے ’’شجرۂ ممنوعہ ‘‘ قرار دیتے ہیں، بعد میں جب خود اپنے اوپر آن پڑتی ہے اور عملاً مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ’’الضرورات تبیح المحظورات‘‘ کے تحت اسے جائز قرار دے دیتے ہیں۔پہلے یہ شکوہ مولوی کو عوام سے ہوتا تھا، لیکن اب خود علماءِ کرام کے حلقے میں بھی یہی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں ۔ مولانا سختی داد نے جس شکوہ کا اظہار کیا ہے، یہ صرف ان کا نہیں،نوے فی صد سے زیادہ علماءِ کرام وفاق المدارس اور بڑے دینی مدارس کے تصویر کو ’’ضرورت‘‘ اور لازمی قرار دینے کی پالیسی پر بعینہ اسی طرح تشویش میں مبتلا ہیں اور یہ تشویش کسی حد تک بجا بھی ہے کیونکہ کل تک ہم ہی تھے جو شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر امورِ دنیا میں تصویر کے ضرورت قرار دینے کو بلاجواز اور اور مسلمان حکم رانو ں کے فسق وفجور پر محمول کرتے تھے ۔ ایسے میں یہ سوال بالکل بدیہی ہے کہ اگر ریاستی اور بین الاقوامی معاملات میں تصویر کی ضرورت مسلمہ نہیں تھی تو ہمارے معمولی تنظیمی اور ادارہ جاتی امور میں یہ ضرورت کیسے متحقق ہوگئی؟ یہی گول مول پالیسیاں اور طرزِ عمل کی عدمِ یکسانیت بعد میں لوگوں کوایسے معاملات پر ازخود رائے زنی کا جواز فراہم کرتی ہے جو ہمیں گراں گزرتی ہے ۔
حواشی
(۱) تفصیل کے لیے دیکھیے: المستصفی للغزالی۱/۱۸۵۔ط:مصری قدیم، (ایضا) فواتح الرحموت لبحرالعلوم العلامۃ عبدالعلی ۲/۲۲۰۔ط:مصری قدیم
(۲) الفقہ علی المذاہب الاربعہ،کتاب الحظر والاباحۃ (احکام التصویر) صفحہ نمبر ۴۳۳۔ط: دارالغد الجدید، مصر
(۳) الفقہ علی المذاہب الاربعہ ، کتاب الحظر والاباحۃ (احکام التصویر) صفحہ نمبر ۴۳۲۔ط:دارالغدالجدید،مصر
(۴) الفقہ علی المذاہب الاربعہ،کتاب الحظر والاباحۃ (احکام التصویر) صفحہ نمبر ۴۳۳۔ط:دارالغدالجدید،مصر
(۵) الفقہ علی المذاہب الاربعہ،کتاب الحظر والاباحۃ (احکام التصویر) صفحہ نمبر ۴۳۳۔ ط: دارالغد الجدید، مصر
(۶) ردالمحتار،باب مایفسد الصلوۃ ومایکرہ فیہا، ۱/۴۷۹۔ط:مصری قدیم
(۷) صحیح البخاری ،کتاب اللباس (باب من کرہ القعود علی الصور)، حدیث نمبر ۵۹۵۷
(۸) صحیح البخاری ،کتاب اللباس (باب من صور صورۃ کلف یوم القیمۃ ۔۔۔)، حدیث نمبر۵۹۶۳
(۹) شرح معانی الآثار ،کتاب الکراہیۃ (باب الصور تکون فی الثیاب) ۴/۱۰۰۔ط:قدیمی کتب خانہ ،کراچی
(۱۰) ان کی عبارت یہ ہے :’’وفی روایۃ النسائی : اما أن تقطع رؤسہا أو تجعل بسطا توطأ، وفی ہذاالحدیث ترجیح قول من ذہب الی أن الصورۃ التی تمتنع الملائکۃ من دخول المکان التی تکون فیہ باقیۃ علی ہیئتہا مرتعفۃ غیر ممتہنۃ ، فأما لوکانت ممتہنۃ أوغیر ممتہنۃ لکنہا غیرت من ہیئتہا اما بقطعہا من نصفہا أو بقطع رأسہا فلاامتناع (فتح الباری ۱۰/۴۸۰۔ط:قدیمی کتب خانہ ،کراچی)
(۱۱) الدرالمختار،باب ما یفسد الصلوۃ ومایکرہ فیہا، ۱/۴۷۹،۴۸۰۔ط: مصری قدیم
(۱۲) حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نورالایضاح ،فصل فی المکروہات من الصلوۃ، صفحہ نمبر ۱۹۹۔ط:مصری قدیم
(۱۳) الفتاوی الہندیۃ ،کتاب الکراہیۃ (الباب الرابع) ۵/۳۱۵۔ ط: مصری قدیم
(۱۴) ردالمحتار،باب ما یفسد الصلوۃ ومایکرہ فیہا، ۱/۴۷۹۔ط:مصری قدیم
(۱۵) امدادالفتاوی ، غناؤ مزامیراور لہوولعب وتصویر کے احکام۴/۲۵۳۔ط:مکتبہ دارالعلوم کراچی
(۱۶) تصویر کے شرعی احکام،صفحہ نمبر۸۶۔ط:ادارۃ المعارف ، کراچی
(۱۷) تصویر کے شرعی احکام،صفحہ نمبر۷۸۔ط:ادارۃ المعارف ، کراچی
(۱۸) فتاوے رضویہ۲۴/۵۷۸،۵۸۹۔ط:رضافاؤنڈیشن،لاہور
(۱۹) تصویر کے شرعی احکام،صفحہ نمبر۴۴۔ط:ادارۃ المعارف ، کراچی
(۲۰) الہدایۃ،باب الأنجاس وتطہیرہا ۱/۱۳۲۔ط: مکتبۃ البشری
(۲۱) ردالمحتار،باب شروط الصلوۃ ۱/۳۰۱۔ط:مصری قدیم
(۲۲) الہدایۃ، باب الجنائز (فصل فی الغسل) ۱/۴۰۸۔ط: مکتبۃ البشری
(۲۳) ردالمحتار،باب شروط الصلوۃ ۱/ ۳۰۱۔ط:مصری قدیم
(۲۴) فتح الباری ۱/ ۶۳۳۔ط:قدیمی کتب خانہ ،کراچی (ایضا) کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ،کتاب الصلوۃ (مبحث ستر العورۃ فی الصلوۃ)، صفحہ نمبر ۱۱۱۔ط: دارالغد الجدید
(۲۵) الہدایۃ ،باب سجودالسہو ۱/۳۳۷،۳۴۰۔ط: مکتبۃ البشری
(۲۶) ملفوظاتِ حکیم الامت ۶/ ۲۱۴۔ط: ادارہ تالیفاتِ اشرفیہ ،ملتان
انا للہ و انا الیہ راجعون
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
قاری محمد عبد اللہؒ
گزشتہ دنوں جامعہ نصرۃ العلوم کے شعبہ حفظ کے سابق صدر مدرس قاری محمد عبد اللہ صاحب طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے پرانے ساتھی اور رفیق کار تھے۔ ان کا تعلق منڈیالہ تیگہ کے قریب بستی کوٹلی ناگرہ سے تھا۔ ان کے والد محترم حاجی عبد الکریم جمعیۃ علماء اسلام کے سرگرم حضرات میں سے تھے اور مفتی شہر حضرت مولانا مفتی عبد الواحد اور امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے تھے۔
انھوں نے اپنے گاؤں میں مسجد بنائی اور تعلیم القرآن کے مدرسہ کا آغاز کیا جس میں علاقہ کے سیکڑوں حضرات نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ راقم الحروف کو ۱۹۷۰ء میں اس بستی میں جانے اور مختلف دینی اجتماعات میں شرکت کی مسلسل سعادت حاصل ہوتی رہی ہے۔ قاری محمد عبد اللہ صاحب نے اس مدرسہ میں سالہا سال تک حفظ قرآن کریم کی تدریس وتعلیم کی خدمات سرانجام دیں۔ پھر کچھ عرصہ تک مدرسہ انوار العلوم جامع مسجد شیرانوالہ باغ میں تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے اور اس کے بعد جامعہ نصرۃ العلوم کے شعبہ حفظ سے منسلک ہو گئے جہاں وہ بیماری اور معذوری تک مسلسل قرآن کریم کی خدمت کرتے رہے۔
قاری صاحب موصوف ایک اچھے استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلکی معاملات اور دینی تحریکات میں بھی سرگرمی کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور ان کا خاص ذوق بزرگوں کی تقاریر اور بیانات کو ریکارڈ کر کے محفوظ کرنے کا تھا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی کے خطبات وبیانات اور دروس ومواعظ کا ایک اچھا ذخیرہ انھوں نے ریکارڈ کر کے محفوظ کر رکھا ہے جو ان کا صدقہ جاریہ رہے گا۔
قاری محمد عبد اللہ صاحب کے کم وبیش سب بیٹے دینی خدمات میں مصروف ہیں جبکہ سب سے بڑے بیٹے مولانا قاری عبید اللہ عامر جامعہ نصرۃ العلوم کے شعبہ حفظ میں ایک عرصہ سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور شہر میں مسلکی جدوجہد اور دینی تحریکات میں پیش پیش رہتے ہیں۔ قاری صاحب کی نماز جنازہ پہلے جامعہ نصرۃ العلوم میں پڑھائی گئی۔ امامت کے فرائض راقم الحروف نے سرانجام دیے جبکہ دوسری نماز جنازہ ان کے بڑے فرزند قاری عبید اللہ عامر صاحب نے گاؤں پڑھائی اور اس کے بعد انھیں کوٹلی ناگرہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
ہم قاری صاحب موصوف کی وفات پر ا س غم میں ان کے خاندان، تلامذہ، احباب اور دیگر متعلقین کے اس غم میں شریک ہیں اور دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت قاری محمد عبد اللہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں اور ان کے پس ماندگان کو صبر وحوصلہ کے ساتھ ان کی حسنات کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین
حضرت قاری عبد الصمدؒ
قرآن کریم حفظ وقراء ت اور تجوید کے بزرگ استاذ حضرت قاری عبد الصمد صاحبؒ بھی گزشتہ دنوں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انھوں نے طویل عرصہ تک مدرسہ اشرف العلوم باغبان پورہ گوجرانوالہ میں تجوید وقراء ت کے شعبہ میں خدمات سرانجام دیں اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ملک کے مختلف حصوں میں قرآن کریم کی خدمت میں مصروف ہے۔
راقم الحروف کو بھی ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہے کہ جامعہ نصرۃ العلوم میں طالب علمی کے دوران چند روز ان کی خدمت میں مشق کے لیے حاضر ہوتا رہا ہوں۔ وہ ایک صاحب فن مقری اور مشفق استاذ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، سیئات سے درگزر فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں اور ان کے تلامذہ وپس ماندگان کو ان کی جلائی ہوئی شمع روشن رکھنے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین یا رب العالمین
مدرسہ نصرۃ العلوم کے قراء کے اعزاز میں تقریب
ادارہ
جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کا قدیم تعلیمی ادارہ ہے جو دینی و علمی مسائل میں اہل وطن کی راہنمائی میں ایک نمایاں مقام کا حامل ہے۔ گزشتہ دنوں اس عظیم علمی مرکز کے ایک قابل و ہونہار استاد قاری وسیم اللہ امین نے پاکستان اور جامعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کویت میں منعقد ہونے والے تجوید و قرأت کے ایک عالمی مقابلہ میں شرکت کی۔ یہ مقابلہ ۱۳؍ اپریل تا ۲۰ اپریل کویت کی ’’وزارت اوقاف و شؤن اسلامیہ‘‘ کے زیر اہتمام کویت کے ’شیراٹن ‘ہوٹل میں منعقد ہوا جس میں ۵۵ کے لگ بھگ ممالک کے قراء کرام نے حصہ لیا۔ قاری وسیم اللہ امین نے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے امیر کویت سے ۹ لاکھ روپے کا نقد انعام اور اعزازی شیلڈ وصول کی ۔اس سے پہلے جا معہ نصرۃ العلوم کے شعبہ حفظ کے استادقاری محمد یاسین صاحب کے فرزنداور مدرسہ نصرۃ العلوم کے طالب علم حافظ عمار یاسر نے جنوری ۲۰۱۱ء کے پہلے ہفتے کے دوران مکہ مکرمہ میں تحفیظ القرآن الکریم کے بین الاقوامی مقابلہ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے ایک لاکھ روپے نقد انعام اور شیلڈ کے مستحق قرار پائے۔ اس مقابلہ کا اہتمام مسجد الحرام میں کیا گیا تھا۔
قاری وسیم اللہ امین اور قاری عمار یاسر کے اعزاز میں۹ ؍مئی ۲۰۱۱ء کو بعد از نماز عصر الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت جامعہ نصرۃ العلوم کے مہتمم مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی نے کی جبکہ ملک کے معروف خطیب مولانا عبد الکریم ندیم مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ پاکستان شریعت کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا قاری جمیل الرحمن اختر، جمعیۃ علماء اسلام آزاد جموں و کشمیر کے سیکرٹری جنرل مولانا عبد الحئی آف دھیر کوٹ اور باغ آزاد کشمیر کے ضلع مفتی مولانا مفتی عبد الشکور بھی تقریب میں موجود تھے جبکہ مدرسہ نصرۃ العلوم کے اساتذہ اور شہر کے علماء کرام و طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ مدرسہ نصرۃ العلوم کے شعبہ تجوید کے صدر مولانا قاری سعید احمد، قاری وسیم اللہ امین اور حافظ عمار یاسرنے تلاوت کلام پاک سے حاضرین کو محظوظ کیا اور مولانا عبدالکریم ندیم نے اپنے مخصوص انداز میں قرآن کریم کی عظمت و حفاظت اور اعجاز کا تذکرہ کرتے ہوئے اس اعزاز پر جامعہ نصرۃ العلوم اور اس کے دونوں سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا زاہد الراشدی نے اس اعزاز پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شرکاے محفل کا شکریہ ادا کیا۔ محفل کے اختتام پر علماء کرام نے الشریعہ اکیڈمی کی لائبریری کا وزٹ کیا اور کتابوں کا وقیع ذخیرہ دیکھ کر اکادمی کی انتظامیہ کے حسن ذوق کو سراہا۔
ہیپا ٹائٹس ۔ کل اور آج
حکیم محمد عمران مغل
کل کی چیونٹی کو آج کا مست ہاتھی کیونکر بنا دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جن معالجین نے علم کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کے نزدیک یہ مست ہاتھی آج بھی محض ایک چیونٹی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پرانے اطبا نے بیماریوں کے بحر ظلمات میں نہ صرف گھوڑے دوڑائے بلکہ حیران کن ریکارڈ بھی قائم کیے۔ تاریخ میں ایسے سیکڑوں واقعات درج ہیں۔
ایسا ہی ایک دلچسپ واقعہ جناب ریٹائرڈ جسٹس الیاس قادری صاحب نے روزنامہ نوائے وقت میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب انھیں عدلیہ میں ملازمت ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ایک دن یرقان نے انھیں آن گھیرا۔ ضابطہ کی کارروائی مکمل کر کے فی الفور تین ماہ کے لیے اسپتال داخل کر دیا گیا۔ دوسرے دن حسب معمول دوست احباب ملنے آئے تو پتہ چلا کہ جسٹس صاحب کو تو اسپتال داخل کر دیا گیا ہے اور کم از کم تین ماہ کا کورس پورا کرنا ہے۔ دوست سیدھے اسپتال پہنچے اور جسٹس صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کو کس نے کہا کہ تین ماہ تک اسپتال میں ایڑیاں رگڑیں؟ ہمارے علم میں اس وقت ایک فرشتہ سیرت حکیم صاحب ہیں، وہ چند دنوں میں آپ کا علاج کر دیں گے۔ جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میرا معالج، میری رہائش، خور ونوش اور میری ملازمت سب سرکاری ہیں اور میں سرتاپا سرکار کی تحویل میں ہوں۔ آپ کی کسی خواہش کی تکمیل میرے بس میں نہیں۔ دوستوں نے ایک نہ سنی اور زبردستی اسپتال سے اٹھا لائے۔
لوہاری دروازہ میں حکیم شیخ محمد حسین کا شہرہ چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ تشخیص اور تجویز ان کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی تھی۔ دو چار منٹ نبض دیکھی اور باتیں کیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ تین چار دن میں اللہ کے فضل سے یرقان نیست ونابود ہو جائے گا، آپ نے ضرور تین ماہ انتظار کرنا ہے؟ چوتھے دن جسٹس صاحب بھلے چنگے ہوئے۔ خوشی خوشی ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میری باقی چھٹی ختم کر کے مجھے نوکری پر بھیجا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تین چار دن میں یرقان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ سرکاری ملازم، پھر بغیر پوچھے اسپتال سے باہر جا کر کسی حکیم سے علاج کرا آئے ہیں۔ پھر آپ کا دعویٰ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوگئے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ میں کسی حکیم یا حکمت کو نہیں مانتا۔ دوستوں نے صورت حال دیکھی تو فوراً حکیم صاحب سے ایک مفصل تصدیق لکھوا کر ساتھ ہی ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ جج صاحب نے فوری طور پر طرفین کو بلایا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کا مریض تین چار دن میں ٹھیک ہو گیا ہے۔ معالج کا حلفیہ بیان بھی مسلک ہے۔ آپ مریض کا تین ماہ مزید علاج کرنے پر کیوں بضد ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے مجلس کو بغور دیکھا، کچھ باتیں کیں، مگر حکیم صاحب نے ایک نہ چلنے دی۔ جج صاحب نے دیکھاکہ ڈاکٹر صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حکیم صاحب کی طرف سے زیر بحث نکتہ یہ ہے کہ آپ یرقان کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے بھری مجلس میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔
میں نے اخبار میں یہ مضمون پڑھ کر شیخ محمد حسین صاحب مرحوم کے خاندان کو ڈھونڈ نکالا۔ ان کے ایک پوتے حکیم جاوید شیخ راوی روڈ لاہور پر مطب کرتے ہیں۔ علیک سلیک کے بعد نسخے پر بات ہوئی تو انھوں نے کہا کہ عام سی گولیاں ہیں۔ اصل نسخہ شربت بزوری معتدل ہی ہے۔ عوام کو بے وقوف بنا کر یرقان کی پانچ اقسام بنا دی گئی ہیں او رہیپا ٹائٹس کا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے انجکشن کا کورس پورا کیا ہے، ان میں سے کچھ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے۔
قارئین کے سامنے مختصر نسخہ عرض کرتا ہوں کہ ابتدا یہاں سے کریں۔ ساری زندگی پانی ابال کر لازماً مٹی کے برتن میں رکھیں اور پئیں۔ سکندر اعظم کی فوج میں براہ راست کنویں، دریا اور چشمے سے پانی لا کر پینا قانوناً جرم تھا۔ چین کے لوگ ہمیشہ نیم گرم پانی پیتے ہیں، اسی لیے میں نے جس مریضہ کا علاج کیا تھا، اسے ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی ہوا سے بچا کر رکھا تھا۔ سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور کر کے پیچش، کھانسی اور بخار چڑھایا۔ اس کے جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے کے لیے کئی جتن کیے۔ اللہ نے میری کوشش کو کامیاب کیا۔ فیثاغورث نے کہا تھا کہ مجھے پانی یا مشروب پینے کے لیے کھلے منہ کا برتن، چمڑے کا جوتا اور کھانے کے لیے موٹا آٹا ملتا رہے تو میں زمین پر بیٹھ کر آسمان کے سارے حالات بتا سکتا ہوں۔ آج کل جتنے رنگین مشروبات استعمال ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں قرشی دواخانہ کے ہر دل عزیز ڈاکٹر جنجوعہ صاحب سے پوچھ لیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں روزانہ کتنا زہر پلایا جا رہا ہے۔ کبھی کھڑے کھڑے پانی نہ پئیں۔ اس سے جگر آناً فاناً کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔
اوپر جتنی باتیں کہی گئی ہیں، ہر بات کی تفصیل کے لیے کئی صفحات درکار ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو بصیرت عطا کی ہے تو ان باتوں کو سمجھ لینے سے صحت کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت سے احباب نے نسخہ جات کے لیے فرمایا ہے۔ یاد رکھیں ہر نسخہ ہر مریض پر کام نہیں کرتا۔ پھر بھی ایک نسخہ عرض کرتا ہوں جو ان شاء اللہ ہر مریض پر کارگر ہوگا۔
جب ہیپا ٹائٹس یعنی یرقان کاحملہ ہو جائے تو بند پیکٹ کی کوئی چیز ہرگز استعمال نہ کریں، ورنہ کینسر کا شدید حملہ ہو سکتا ہے۔ حملے کے بعد عرق مکوہ اور عرق کاسنی آدھا آدھا کپ ملا کر دن میں تین بار پئیں۔ انار یا شربت انار، املی آلو بخارے کا شربت، کنو، مالٹا، سنگترہ جو میسر ہو، استعمال میں لائیں۔ ساری زندگی پانی ابال کر پینے والے کو یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بازاری شربت اور بوتلیں گردوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہیں، اس لیے کہ تمام رنگین اشیا کا رنگ گردے میں پتھری کا باعث بنتا ہے۔ گردے اس رنگ کو چھانٹ لیتے ہیں۔
جولائی ۲۰۱۱ء
امیر عبد القادر الجزائریؒ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(جان کائزر کی کتاب ’’امیر عبد القادر الجزائری: سچے جہاد کی ایک داستان‘‘ کے دیباچہ کے طور پر لکھا گیا۔)
انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی کے دوران مسلم ممالک پر یورپ کے مختلف ممالک کی استعماری یلغار کے خلاف ان مسلم ممالک میں جن لوگوں نے مزاحمت کا پرچم بلند کیا اور ایک عرصہ تک جہاد آزادی کے عنوان سے داد شجاعت دیتے رہے، ان میں الجزائر کے امیر عبد القادر الجزائریؒ کا نام صف اول کے مجاہدین آزادی میں شمار ہوتا ہے جن کی جرات واستقلال، عزیمت واستقامت اور حوصلہ وتدبر کو ان کے دشمنوں نے بھی سراہا اور ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔
امیر عبد القادر مئی ۱۸۰۷ء میں الجزائر میں، قیطنہ نامی بستی میں ایک عالم دین اور روحانی راہنما الشیخ محی الدینؒ کے ہاں پیدا ہوئے اور اپنے والد محترم سے اور ان کے زیر سایہ دیگر مختلف علماء کرام سے ضروری دینی وعصری تعلیم حاصل کی اور ان کے ساتھ ۱۸۲۵ء میں حج بیت اللہ کی سعادت سے بھی بہرہ ور ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مغرب کے استعماری ممالک ’’انقلاب فرانس‘‘ کی کوکھ سے جنم لینے والی جدید مغربی تہذیب وثقافت کی برتری کے نشے سے سرشار تھے اور سائنسی ترقی سے حاصل ہونے والی عسکری قوت اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت نے انھیں پوری دنیا پر حکمرانی کا شوق دلا دیا تھا۔ عالم اسلام کی دو بڑی قوتیں خلافت عثمانیہ اور مغل بادشاہت ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں، چنانچہ برطانیہ، فرانس، اٹلی، ہالینڈ، پرتگال اور دوسرے ممالک نے ان دونوں قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مختلف اطراف میں یلغار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ افریقہ اور ایشیا کے ایک بڑے حصے کو نو آبادیات میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ اور مغل بادشاہت کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ سائنسی ترقی اور دنیا میں ہونے والی تہذیبی ومعاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کا بروقت ادراک نہ کر سکیں اور ان کی یہ غفلت استعماری یلغار کے سامنے عالم اسلام کے ایک بڑے علاقے کے سرنڈر ہونے کے اسباب میں ایک اہم سبب ثابت ہوئی۔
بہرحال جب بہت سے مسلم ممالک نے مختلف یورپی ممالک کی نوآبادیاتی غلامی کا طوق گردنوں میں پہنا تو ہر جگہ حریت پسندوں اور آزادی کے متوالوں نے حالات کے اس جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور بہت دیر تک بغاوت اور سرکشی کا محاذ گرم رکھا۔ الجزائر پر فرانس کے تسلط کا آغاز انیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آخر میں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب جنوبی ایشیا میں برطانوی تسلط ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہو چکا تھا اور امام ولی اللہ دہلویؒ کے مکتب فکر بلکہ خانوادے سے تعلق رکھنے والے مجاہدین کا ایک گروہ سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی قیادت میں پشاور کے علاقے میں جہادی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ ان کا وقتی سامنا اگرچہ سکھوں سے تھا، لیکن اپنے عزائم اور اہداف کے حوالے سے وہ برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف جہاد کے لیے بیس کیمپ حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ اس قافلہ حریت نے ۱۸۳۰ء میں پشاور کے صوبہ پر قبضہ اور کم وبیش سات ماہ حکومت کرنے کے بعد ۶؍ مئی ۱۸۳۱ء کو بالاکوٹ میں جام شہادت نوش کیا تھا۔
الجزائر میں جب ۱۸۳۰ء میں فرانس نے تسلط قائم کرنے کی کوشش کی تو علماء کرام اور مجاہدین کی ایک جماعت نے امیر عبد القادرؒ کے والد محترم الشیخ محی الدینؒ کی قیادت میں تحریک مزاحمت کا آغاز کیا، مگر دو سال کے بعد ۱۸۳۲ء میں یہ دیکھتے ہوئے کہ اس مزاحمت کا سلسلہ بہت دیر تک قائم رہ سکتا ہے، تحریک مزاحمت کی مستقل منصوبہ بندی کی گئی اور الشیخ محی الدین کے جواں سال اور جواں ہمت بیٹے امیر عبد القادر کو باقاعدہ امیر منتخب کر کے مزاحمت کی جدوجہد کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔
امیر عبد القادرؒ جذبہ جہاد کے ساتھ ساتھ فراست وتدبر کی نعمت سے بھی مالامال تھے، اس لیے انھوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے الجزائری عوام اور قبائل کو اعتماد میں لیا، وسیع تر مشاورت کا سلسلہ قائم کیا، آزادی کی فوج کو وقت کے ہتھیاروں اور جنگ کی نئی تکنیک سے مسلح کیا اور ایک باقاعدہ فوج منظم کر کے الجزائر پر حملہ آور فرانسیسی فوجوں کے خلاف میدان جنگ میں نبرد آزما رہے۔ انھوں نے ۱۸۳۲ء سے ۱۸۴۷ء تک مسلسل سولہ سال تک فرانسیسی فوجوں کے خلاف جنگ لڑی، بہت سے معرکوں میں فرانسیسی فوجوں کو شکست سے دوچار کیا اور ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر کے امارت شرعیہ کا نظام قائم کیا۔ وہ اس وقت تک لڑتے رہے جب تک الجزائری عوام اور اسباب ووسائل نے ان کا ساتھ دیا اور جب حالات کی نامساعدت نے انھیں بالکل تنہا کر دیا اور الجزائر کے قبائل ایک ایک کر کے الگ ہوتے گئے تو ۱۸۴۸ء میں انھوں نے اور کوئی چارۂ کار نہ دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔
انھیں گرفتار کر کے ۱۸۵۳ء تک فرانس کے مختلف قلعوں میں محبوس رکھا گیا اور پھر آزاد کر کے دمشق کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ انھوں نے ۲۳؍ دسمبر ۱۸۴۷ء کو ایک مشروط معاہدے کے تحت خود کو فرانسیسیوں کے حوالے کیا تھا، مگر ان کی شرائط کو قبول کیے جانے کے بعد بھی حسب معمول بالاے طاق رکھ دیا گیا تو ایک موقع پر انھوں نے اس حسرت کا اظہار کیا کہ:
’’اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے جو ہو رہا ہے تو ہم جنگ ترک نہ کرتے اور مرتے دم تک لڑتے ہی رہتے۔‘‘
وہ پہلے استنبول گئے اور پھر خلافت عثمانیہ کی ہدایت پر دمشق آ گئے جہاں انھوں نے درس وتدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ مالکی فقہ کے بڑے علما میں سے تھے اور تصوف میں الشیخ الاکبر محی الدین بن عربیؒ کے پیروکار اور ان کے علوم کے شارح تھے۔ دمشق میں قیام کے دوران انھیں ایک اور معرکے سے سابقہ درپیش ہوا کہ خلافت عثمانیہ کی طرف سے شام میں مقیم مسیحیوں پر جزیہ کا قانون تبدیل کیے جانے کے بعد اس مسئلے پر مسلم مسیحی کشمکش کا آغاز ہوا اور بہت سے حلقوں کی طرف سے قانون کی اس تبدیلی کو ناکام بنانے کے لیے مسیحیوں کے خلاف مسلمان عوام کو بھڑکانے کا سلسلہ شروع کیا گیا جس پر امیر عبد القادر الجزائریؒ نے مسیحیوں کے خلاف اس یلغار کی مخالفت کی اور ان کی حمایت وتحفظ کے لیے کمربستہ ہو گئے۔ اس وقت غصے میں بپھرے ہوئے عوام کے لیے امیر عبد القادر کا یہ اقدام قابل اعتراض تھا، لیکن وہ اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ بے گناہ مسیحیوں کی جانیں بچانا ان کا شرعی فریضہ ہے اور وہ ایسا کر کے اپنے اسلامی فرض کی تکمیل کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ امیر عبد القادر الجزائری کے اس جرات مندانہ اقدام کی وجہ سے کم وبیش پندرہ ہزار مسیحیوں کی جانیں بچیں جس کی وجہ سے انھیں مغربی دنیا میں بھی تحسین کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور انھیں ’’امن کا ہیرو‘‘ قرار دے کر مغرب کے چوٹی کے سیاسی راہ نماؤں اور دانش وروں نے خراج تحسین پیش کیا، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے ان کے کردار کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ ’’عبدالقادر کے لیے یہ یقیناًعظمت کا اور حقیقی شان وشوکت کا باب ہے۔ اس بات کو تاریخ میں رقم کرنا کوئی معمولی بات نہیں کہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے لڑنے والا سب سے ثابت قدم سپاہی اپنے سیاسی زوال اور اپنی قوم کے ناگفتہ بہ حالات میں عیسائیوں کی زندگیوں اور حرمت کا سب سے نڈر نگہبان بن کر سامنے آیا۔ جن شکستوں نے الجزائر کو فرانس کے آگے جھکایا تھا، ان کا بدلہ بہت حیرت انگیز طریقے سے اور اعلیٰ ظرفی سے لے لیا گیا ہے۔‘‘
امیر عبد القادر الجزائری کا یہ کردار دیکھ کر مجھے متحدہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک بڑے لیڈر مولانا عبید اللہ سندھیؒ یاد آ جاتے ہیں اور مجھے ان دونوں بزرگوں میں مماثلت کے بعض پہلو بہت نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً مولانا عبید اللہ سندھیؒ اگرچہ میدان جنگ کے نہیں، بلکہ میدان فکر وسیاست کے جرنیل تھے، مگر ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں سیاست وجنگ کے روایتی طریقوں پر قناعت کرنے کی بجائے ان جدید اسالیب، تکنیک اور ہتھیاروں کو سیاست اور جنگ کے دونوں میدانوں میں اختیار کرنا چاہیے اور وہ عمر بھر اسی کے داعی رہے۔
انھوں نے جب دیکھا کہ وہ حرب وجنگ کے ذریعے سے برطانوی تسلط کے خلاف جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو انھوں نے اس معروضی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی جدوجہد کے لیے عدم تشدد کا راستہ اختیار کر لیا اور بقیہ عمر پرامن جدوجہد میں بسر کر دی۔
امیر عبد القادر کی طرح مولانا سندھی نے بھی عملی تگ وتاز کے میدان کو اپنے لیے ہموار نہ پاتے ہوئے تعلیم وتدریس کا راستہ اختیار کیا اور ہندوستان واپسی کے بعد دہلی اور دوسرے مقامات میں قرآن کریم کے تعلیمی حلقے قائم کر کے اپنے فکر وفلسفہ کی تدریس وتعلیم میں مصروف ہو گئے۔
مولانا سندھیؒ مغربی تہذیب وثقافت اور تکنیک وصلاحیت کی ہر بات کو مسترد کر دینے کے قائل نہیں تھے، بلکہ اس کی ان باتوں کو اپنانے کے حامی تھے جو اسلامی اصولوں سے متصادم نہیں ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اس کی وجہ سے انھیں بہت سے حلقوں کی طرف سے مطعون بھی ہونا پڑا۔
امیر عبد القادر الجزائری کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کا پیروکار، ان کے علوم کا شارح اور ان کے فلسفہ وحدت الوجود کا قائل ہونے کی وجہ سے ان کے فکر کے ڈانڈے ’’وحدت ادیان‘‘ کے تصور سے ملانے کی کوشش کی گئی (جس کی جھلک جان کائزر کی زیر نظر کتاب میں بھی دکھائی دیتی ہے)، حالانکہ وحدت الوجود اور وحدت ادیان میں زمین وآسمان کا فرق ہے اور شیخ اکبرؒ کے نظریہ وحدت الوجود کا مطلب وحدت ادیان ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی کو بھی فرنگی تسلط کے خلاف سیاسی طور پر ہندوستانی اقوام کے ’’متحدہ قومیت‘‘ کے نظریہ پر ہدف تنقید بنایا گیا اور انھیں ’‘وحدت ادیان‘‘ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔
امیر عبد القادر الجزائریؒ مغربی استعمار کے تسلط کے خلاف مسلمانوں کے جذبہ حریت اور جوش ومزاحمت کی علامت تھے اور وہ اپنی جدوجہد میں جہاد کے شرعی واخلاقی اصولوں کی پاس داری اور اپنے اعلیٰ کردار کے حوالے سے امت مسلمہ کے محسنین میں سے ہیں۔ ان کے سوانح وافکار اور عملی جدوجہد کے بارے میں جان کائزر کی یہ تصنیف نئی پود کو ان کی شخصیت اور جدوجہد سے واقف کرانے میں یقیناًمفید ثابت ہوگی۔ ایسی شخصیات کے ساتھ نئی نسل کا تعارف اور ان کے کردار اور افکار وتعلیمات سے آگاہی استعماری تسلط اور یلغار کے آج کے تازہ عالمی منظر میں مسلم امہ کے لیے راہ نمائی کا ذریعہ ہے اور اس سمت میں کوئی بھی مثبت پیش رفت ہمارے لیے ملی ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے۔
اسلام میں سماجی طبقات ۔ سورۂ زخرف کی آیت ۳۲ کی روشنی میں
ڈاکٹر حافظ محمد شکیل اوج
سورۂ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
أَہُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَۃَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْْنَہُم مَّعِیْشَتَہُمْ فِیْ الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَہُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُہُم بَعْضاً سُخْرِیّاً وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ (زخرف، ۳۲)
اس آیت میں لِیَتَّخِذَ بَعْضُہُم بَعْضاً سُخْرِیّاً کے الفاظ ہماری بحث کا اصل موضوع ہیں اور انھی سے ہمارے مضمون کا عنوان متعین ہوا ہے۔ مذکورہ بالا الفاظ کا معنی بالعموم یہ کیا جاتا ہے:
’’تاکہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں مدد کے لیے لے سکیں۔‘‘ (ابو الکلام آزادؒ ) ۱
’’تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں۔‘‘ (مولانا وحید الدین خان) ۲
تاہم ان الفاظ کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے، جسے میں یہاں خصوصی معنی سے تعبیر کرتا ہوں:
’’کہ ان میں سے ایک دوسرے کی ہنسی بنائے۔‘‘ (مولانا احمد رضا خان بریلویؒ ) ۳
’’کہ انجام کار یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔‘‘ (مولانا غلام رسول سعیدی) ۴
زیر نظر مضمون میں ہم اس فقرے کو آیت کے محل میں اور آیت کو اس کے سیاق وسباق میں دیکھیں گے تاکہ معروضی طور پر عطر حقیقت کشید ہو سکے اور اس فقرے کی صحیح تعیین راجح شکل میں متعین ہو سکے۔
اس آیت کا ایک ترجمہ حسب ذیل ہے:
’’کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پرفوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔‘‘ ۵
اور اب ثانی الذکر یعنی خصوصی معنی کے تحت ترجمہ ملاحظہ ہو:
’’کیا یہ (کفار) آپ کے لیے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے کہ انجام کار یہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔‘‘ ۶
اول الذکر ترجمے میں جو کہا گیا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے:
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت ورسالت پر کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے کسی مال دار آدمی کو کیوں نہ چنا؟ اسی تناظر میں کفار کا ذکر صیغہ غائب میں کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ (اے رسول محترم!) تیرے پروردگار کی تقسیم کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دنیوی زندگی کی روزی کی تقسیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے اصول آزمائش کے تحت ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ یہ مدارج فوقیت اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے خدمت واجرت اور تعاون کے کام لے سکیں اور (اے رسول محترم) تیرے پروردگار کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر ہے۔
مولانا امین احسن اصلاحی نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:
’’..... یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نظام اس نے اس طرح کا رکھا ہے کہ اس میں ہر شخص دوسروں کا محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دوسروں کا محتاج ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس میں محتاج الیہ ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص دوسروں سے مستغنی نہیں ہے اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ معاشرے میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کی افادیت نہ ہو......۷
اسی تصور کو ذرا مخصوص اور ایڈوانس شکل میں مفتی محمد تقی عثمانی نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے:
’’ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے ایک، دوسرے سے کام لے سکے۔
ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے کام اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی طلب ہے اور کام دینے والا کام کی رسد ہے۔ اس طلب ورسد کی باہمی کشمکش اور باہمی امتزاج سے ایک متوازن معیشت وجود میں آتی ہے۔‘‘ ۸
آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس آیت سے حیرت انگیز طو رپر طلب ورسد کا معاشی قانون دریافت فرمایا ہے، حالانکہ اس آیت سے نہ قانون طلب کشید ہوتا ہے اور نہ قانون رسد۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں سے جزء اً جزء اً جب ا س طرح استدلال کیا جاتا ہے تو پھر ایسا ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، البتہ استقرا کے اسلوب پر قرآن مجید سے استدلال کرنے کا نتیجہ اس سے قطعی مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے مجتہد کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو بحیثیت مجموعی ملحوظ رکھ کر استدلال کرے تاکہ امکان خطا کم سے کم رہ جائے۔ اس ضمن میں تصریف آیات اور نظم قرآن کا اصول اگر پیش نظر رہے تو مجتہد قرآن کی مراد تک بہ آسانی پہنچ سکتا ہے۔
اب ہم آیہ زیر بحث کے سیاق وسباق کو دیکھتے ہیں تاکہ آیت اپنے مفہوم کو خود متعین کر دے۔ آیت زیر بحث سے قبل یہ فرمایا گیا ہے:
وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ ہَذَا الْقُرْآنُ عَلَی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْیَتَیْْنِ عَظِیْمٍ (زخرف ۳۱)
’’اور انھوں نے کہا: یہ قرآن ان دو شہروں (مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا؟‘‘
اس کی تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے مزعومہ خیال کے مطابق دنیاوی اعتبار سے اسے کسی بڑے آدمی کا استحقاق سمجھا تھا۔ ان کے نزدیک حضور اس رحمت کے سزاوار نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیوی اعتبار سے کسی آدمی کا بڑا ہونا اس کی معیشت سے وابستہ ہوتا ہے۔ معیشت میں جس درجے کی وسعت وکشادگی یافخر وطمطراق پایا جاتا ہے، آدمی کی شخصیت اسی درجے کی عظمت ورفعت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔
نبوت ورسالت کا انتخاب چونکہ دنیوی اکتساب کے میدانوں سے نہیں، بلکہ محض خداکی چاہت سے ہوتا ہے، اس لیے اسے معیشت سے وابستہ کرنا سفلی تخیل کے سوا کچھ نہیں۔ بایں طور اس آیت میں کفار کی جانب سے حضور علیہ السلام کا استخفاف مذکور ہوا ہے، اس لیے اگلی آیت میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ استفہام دراصل کفار کے استخفاف کا منہ توڑ جواب ہے۔ پھر تقسیم رحمت اور تقسیم معیشت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت وحکمت سے وابستہ کر کے استخفاف کرنے والوں کو سمجھایا کہ خدا کی تقسیم معیشت میں لوگوں کو جو متفاوت رکھا گیا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا استہزا کریں اور مذاق اڑائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اسے خدا کی ایسی حکیمانہ تقسیم سے تعبیر کریں جس کے نتیجے میں عملی تعاون کی صورت پیدا ہو، یعنی معیشت کی فراوانی سے لوگوں کو مسخر کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، کیونکہ اس جذبہ تسخیر سے لوگوں میں جاگیردارانہ اور وڈیرانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے اور استحصال کا رویہ جنم لیتا ہے۔ پھر اسی سوچ سے لوگوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے جیسا کہ آیت نمبر ۳۱ سے عیاں ہے۔
چنانچہ آیت نمبر ۳۲ کے زیر بحث فقرے کا صحیح محل وہ ہے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی اور مولانا غلام رسول سعیدی کے تراجم سے واضح ہے، اس لیے کہ مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا وحید الدین خان کے ترجموں سے قرآن کی مقصدیت واضح نہیں ہوتی۔ عمومی تراجم کی رو سے جو تفسیریں کی گئی ہیں، اس سے معیشت میں متفاوت ہونے کے سبب مستقل بنیادوں پر بعض کو بعض کا مخدوم اور خادم ماننا پڑتا ہے اور یوں معاشی بنیاد پر ایک ایسا طبقاتی سماج وجود پذیر ہو جاتا ہے جسے قرآن کی تائید (Sanction) حاصل ہونے کے سبب مذہبی تقدس بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے سماج میں معاشی تفریق وامتیاز کو خدا کی ایک ایسی تقسیم سمجھ لیا جاتا ہے کہ جسے قائم کرنا اور رکھنا خود خدا کا گویا مطالبہ قرار پاتا ہے، چنانچہ لیتخذ بعضہم بعضہم سخریا کے اس معنی کو ہر دور میں سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں لازمی عنصر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اسے خدا کی تقسیم کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے عمومی مطالعہ سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ قرآن انسانی سماج کو سرمایہ دارانہ نظم معیشت سے بچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ آیت زیر بحث سے اس طرح کا استدلال خود قران کے مقصود ومدعا کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ کم از کم قرآن کے استقرائی اسلوب سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔
آیت زیر بحث کے مابعد آیات میں جو مضمون آیا ہے، وہ بھی اسی مفہوم کا موید ہے۔ ملاحظہ کیجیے:
وَلَوْلَا أَن یَکُونَ النَّاسُ أُمَّۃً وَاحِدَۃً لَجَعَلْنَا لِمَن یَکْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُیُوتِہِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّۃٍ وَمَعَارِجَ عَلَیْْہَا یَظْہَرُونَ، وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَیْْہَا یَتَّکِؤُونَ، وَزُخْرُفاً وَإِن کُلُّ ذَلِکَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃُ عِندَ رَبِّکَ لِلْمُتَّقِیْنَ (زخرف ۳۳۔۳۵)
’’اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے ؟؟ بھی اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہیں اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔‘‘ ۹
ان آیات کی تفسیر میں مولانا وحید الدین نے لکھا ہے:
’’پیغمبر اسلام جب مکہ میں ظاہر ہوئے تو اس وقت وہ لوگوں کو ایک معمولی انسان نظر آتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کو اگر اپنا کوئی نمائندہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو اس نے عرب کی مرکزی بستیوں (مکہ اور طائف) کی کسی عظیم شخصیت کو اس کے لیے کیوں نہیں چنا۔ مگر یہ ان کی نظر کی کوتاہی تھی۔ انسان صرف حال کو دیکھ پاتا ہے، جبکہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے مستقبل کو دیکھنے والی نظر درکار تھی۔ چونکہ لوگوں کو اس قسم کی دور بیں نظر حاصل نہ تھی، وہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔
پیغمبر اسلام کو کم سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی زندگی میں مادی چیزوں کی رونق لوگوں کو دکھائی نہ دیتی تھی، مگر ان مادی چیزوں کی خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں خدا کی نظر میں اتنی غیر اہم ہیں کہ وہ چاہے تو لوگوں کو سونے چاندی کا ڈھیر دے دے، مگر خدا نے ایسا نہیں کیا کہ لوگ انھی چیزوں میں اٹک کر رہ جائیں گے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر حقیقت کو نہ پا سکیں گے۔‘‘ ۱۰
اس تفسیر نے واضح کر دیا ہے کہ کفار مکہ نے چونکہ حضور علیہ السلام کو معاشی طور پر ادنی آدمی سمجھا ہوا تھا، اس لیے وہ ان سے ہدایت کے طالب نہیں ہونا چاہتے تھے اور یہ ایک طرح سے ذات نبوی کا استخفاف تھا۔ پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے معاشی درجات میں فرق مراتب کو لوگوں کے مابین استخفاف واستہزا کا نہ صرف سبب قرار دیا بلکہ انھیں ایسا کرنے سے منع بھی کیا۔ مطلب یہ کہ لوگوں میں یہ فرق اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ اسے بنیاد بنا کر لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ قرآن مجید کے اس مقصود ومدعا تک بہت کم مترجمین پہنچ پائے ہیں۔ عصر حاضر کے نامور عالم دین پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنے ترجمے میں اس مدعاے قرآنی کو بہت عمدگی سے بیان کیا ہے:
’’کیا آپ کے رب کی رحمت (نبوت) کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کے (اسباب) معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر (وسائل ودولت میں) درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ (کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں) کہ ان میں بعض (جو امیر ہیں) بعض (غریبوں) کا مذاق اڑائیں؟ (یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حق دار ہی نہ سمجھو) اور آپ کے رب کی رحمت اس (دولت) سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے (اور گھمنڈ کرتے ہیں)۔‘‘ ۱۱
واضح ہو کہ اس فکر کی تائید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ترجمہ قرآن میں بھی موجود ہے:
’’...... وبلند مرتبہ ساختیم بعض ایشان را بعض تا تمسخر گیرد بعض ایشان بعضے را .....‘‘ ۱۲
آپ نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ تمسخر کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے یہ مفہوم امام قرطبیؒ کی تفسیر میں بھی موجود ہے: ’ہو من السخریۃ التی بمعنی الاستہزاء ای یستہزئ الغنی بالفقیر‘ ۱۳
امام قرطبی نے معروف معنی کے ساتھ سخریۃ کا یہ معنی بھی نقل کیا ہے جو استہزا کے مفہوم پر متضمن ہے، یعنی وہ توہین جو کوئی مال دار کسی غریب کی کرتا ہے۔
افسوس کہ یہ انقلابی مفہوم امت میں رائج اور شائع نہ ہو سکا اور شاید اس کا سبب جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کا غلبہ واستیلا رہا، مگر اب لوگوں کا قرآنی شعور بڑھ رہا ہے۔ لوگ اپنے مسائل کا ادراک اور اس کا حل قرآنی افکار سے طے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جدید مترجمین میں قرآنی مقصدیت سے مالامال یہ توانا فکر روز بروز پروان چڑھ رہی ہے۔ ماضی قریب کے ایک بزرگ عالم دین علامہ احمد سعید کاظمیؒ کے ترجمے میں بھی یہ حسن فکر ونظر موجود ہے:
’’..... اور ہم نے (دنیوی نعمتوں میں) انھیں ایک دوسرے پر بدرجہا فوقیت عطا فرمائی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور آپ کے رب کی رحمت اس چیز سے بہت بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔‘‘ ۱۴
آخر میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ مقدم الذکر یعنی عمومی فکر کی رو سے جو تراجم کیے گئے ہیں، وہ بھی بلاشبہ امر واقعہ کے طور پر اپنے محل میں صحیح بیٹھتے ہیں، مگر اس امکان غالب کے ساتھ کہ اس میں ایسے واقعاتی شہادات موجود ہیں جن کی تعبیر وتفسیر مثبت ومنفی ہر دو طرح سے ممکن ہے، جبکہ موخر الذکر یعنی خصوصی فکر کی رو سے قرآن کے قاری کو ایک ایسا منہاج عطا ہوتا ہے جس کی انقلاب آفریں تعبیر وتفسیر اول وآخر مثبت ہی مثبت اور ہر طرح کی منفیت سے محفوظ ہے اور یہی اس فکر کا حسن وکمال ہے۔
حوالہ جات
۱ ترجمان القرآن، جلد سوم ص ۱۳۷، مرتبہ: غلام رسول مہر، شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۱۹۶۰ء
۲ تذکیر القرآن، جلد دوم، دار التذکیر، رحمن مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، ۲۰۰۵ء
۳ کنز الایمان، ناشر: المجدد احمد رضا اکیڈمی، کراچی ۱۹۷۶ء
۴ تبیان القرآن، فرید بک اسٹال، لاہور، ۲۰۰۵ء
۷ تدبر قرآن، جلد ہفتم ص ۲۲۶، فاران فاؤنڈیشن، لاہور ۱۹۸۸ء
۸ اسلام اور جدید معیشت وتجارت، ص ۴۲، ادارۃ المعارف کراچی، ۱۹۹۶ء
۱۱ عرفان القرآن، منہاج القرآن پبلی کیشنز، لاہور، اشاعت ہفت دہم، ۲۰۰۶ء
۱۲ فتح الرحمن، ناشر: الامیر الولید بن طلال بن عبد العزیز آل سعود، ۱۴۱۶ھ۔ ترجمہ کے حاشیہ میں یہ عبارت درج ہے: بچشم حقارت نگرد۔
۱۳ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، الجزء السادس، الناشر: دار الکاتب العربی للطباعۃ والنشر بالقاہرۃ، ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء
سماجی، ثقافتی اور سیاسی دباؤ اور دین کی غلط تعبیریں
ڈاکٹر حافظ صفوان محمد چوہان
اللہ نے دین کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ صحابۂ کرام علیہم الرضوان میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور اُن میں بھی ایسے لوگ گنتی کے چند تھے کہ جنھیں دین فہمی میں رسوخ کا وہ درجہ حاصل تھا کہ اُن کے لیے زبانِ نبوت سے ’’فقیہ‘‘ کا جاوداں لقب حاصل ہوا۔ بحیثیت مجموعی یہ وہ لوگ تھے جن کو صحبت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جوہر عطا ہوا تھا کہ جس کو کسی بھی بڑی سے بڑی نعمت کا مثل بتانے میں زمین و آسمان کی کل نعمتوں میں سے کسی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤسسِ دعوت و تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نظریۂ تعلیم و تعلم کا ذکر بایں الفاظ کیا ہے: ’’دین کا کچھ حصہ جوارح سے تعلق رکھتا ہے، وہ جوارح کی حرکت ہی سے حاصل ہوگا۔ کچھ حصہ قلب سے تعلق رکھتا ہے، وہ قلب سے قلب میں منتقل ہوسکتا ہے۔ کچھ حصہ ذہن سے، وہ بے شک کتابوں کے صفحات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔‘‘ صحابہ کرام کی اکثریت دین کے اُس حصے کی حامل تھی جو اعضا و جوارح کی حرکت سے متعلق ہے۔ اُن کے اند ر دین متین کا یہ حصہ رچ بس گیا تھا۔ چنانچہ دین کے اِس حصے کو لے کر وہ جہاں گئے، دین کے اِس حصے کو زندہ کرتے چلے گئے۔ چند عشروں میں خدا کی پوری معلوم دنیا جسم سے نکلنے والے اعمال یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادتین سے آشنا ہوگئی۔ دین دین کی محنت سے زندہ ہوتا ہے؛ باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں۔
اللہ نے دین کو آسان کیا۔ لوگ اپنی ناسمجھی، معاشرتی دباؤ اور بسا اوقات عقیدت کی کسی خاص لہر میں آکر اِسے مشکل بنالیتے ہیں۔ ذیل کی سطروں میں ایسی ہی چند غلط فہمیوں کا بیان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقتِ مقرر پر فرض کیا ہے اور پوری دنیا کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ کسی نماز کو کسی خاص مسجد یا امامِ مسجد سے مخصوص کرلینا صرف ذوقی چیز ہے جس پر اصرار درست نہیں۔ مسجد بیت الحرام، مسجد نبویؐ اور مسجدِ بیت المقدس کے علاوہ دنیا کی تمام مساجد میں نماز کا ایک ہی جتنا اجر ہے، اور اِن تین مساجد کے علاوہ کسی بھی جگہ کے سفر کو عبادت کی نیت سے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی مذہبی جماعت کے صدر مقام پر برائے تربیت و اصلاح جانے والوں کو اپنی نیت کی درستی خاص طور سے کرنی چاہیے کہ وہاں کی گئی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی خاص درجہ نہیں ہے۔ یا مثلاً کسی کام کے ہوجانے پر کسی خاص مسجد میں نفل وغیرہ پڑھنے کی منت مان لی جائے، یہ بھی درست نہیں۔ نفل ضرور پڑھنے چاہییں اور اُن کی منت بھی مانگی جانی چاہیے، لیکن اِس ادائیگی کو کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے وہ بندے جو قضائے عمری ادا کرتے ہیں، اُنھیں یہ بتایا جانا چاہیے کہ قضا صرف فرض نماز کی ہے جس میں نمازِ عشا کے تین وتر بھی آتے ہیں۔ عیدِ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی مطلب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی ہے۔ اِس روز نماز سمیت کسی بھی عبادت کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اِس عید (یعنی خوشی) کی کوئی نماز ہے۔ نمازِ عشا کے بعد پڑھے جانے والے تمام نفل رات کی نماز یعنی تہجد کی تعریف میں شامل ہیں۔
صلوٰۃِ تسبیح کی جماعت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ نمازوں میں صرف سورۂ اخلاص اور سورۂ کوثر پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، ایسا درست نہیں۔ فجر کی سنتوں کی وجہ سے اگر جماعت جاتی ہو تو اِنھیں موخر کردینا چاہیے۔ نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بند کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اِس میں جلدی کرنی چاہیے اور بٹنوں کو خوامخواہ ٹٹولنا نہیں چاہیے۔ جمعے کا خطبہ اور عیدین کے خطبے اپنے آداب کے اعتبار سے نماز ہائے جمعہ و عیدین کا ویسے ہی حصہ ہیں جیسے کہ نماز میں التحیات ہوتی ہے۔ اِن خطبوں کے دوران کوئی بات کی جائے یا کسی بات کا جواب دیا جائے یا محض اشارہ ہی کیا جائے یا کوئی نماز ہی پڑھی جائے تو خطبہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اِس کا اجر نہیں ملتا۔ نمازیوں کا اِن خطبوں کو سننا خطیب کا حق ہے۔ باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے کئی درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے چنانچہ جہاں تک ہوسکے، نمازِ باجماعت کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اِس لیے بھی کہ پوری جماعت میں ایک بھی آدمی کی نماز قبول ہوجائے تو جماعت کی برکت سے سبھی کی نماز قبول کرلیے جانے کی امید ہے۔
نمازِ باجماعت، جمعہ اور عیدین کا اہتمام عورتوں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو اہل خانہ کو چاہیے کہ عورتوں کے مسجد میں جاکر نماز ادا کرنے میں بلا وجہ رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے یعنی اُنھیں عورتوں پر برتری دی ہے۔ مردوں کے ذمے ہے کہ عورتوں کے لیے باجماعت نماز کی ادائیگی کی صورتیں بنائیں، ورنہ خدا کے ہاں اپنا جواب سوچ رکھیں۔ مسجدیں صرف مسلمان مردوں کے لیے تربیت گاہیں یا میل جول کے مقامات (Community centres) نہیں ہیں بلکہ عورتوں اور بچوں کے لیے بھی ہیں۔ مسجدِ نبوی شریف میں عورتیں بھی تشریف لایا اور جمع ہوا کرتی تھیں۔ مسجد میں بچوں کو ضرور لے جانا چاہیے کیونکہ صحابہ کرام ایسا کرتے رہے ہیں۔ حضرات حسنین کریمینؓ اور حضرت امامہ بنتِ عثمان رضی اللہ عنہا تو اپنے بچپن میں مسجدِ نبوی شریف میں آکر کھیلتے بھی رہے ہیں۔ دودھ پیتے بچے روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیا کرتے۔ معلوم ہوا کہ اُس دور میں عورتیں شیر خوار بچوں کو بھی مسجد نبوی شریف میں لایا کرتی تھیں اور آج تک لاتی ہیں۔
ہر آزاد مسلمان (مرد ہو یا عورت) پر نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ ہوا میں اُڑ رہا ہو یا پانی میں ڈوب ہی کیوں نہ رہا ہو۔ نماز کو چھوڑ کر مخیر یا بااخلاق بننے کی کوشش کرنا سخت بھول ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کی حیثیت دین میں ویسی ہے جیسی بدن میں سر کی ہے، چنانچہ اِس کے قیام کے بغیر اسلام کا دعویٰ ہی بے دلیل ہے۔ اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے، اِس لیے اِس کی خاص طور سے فکر کرنی چاہیے۔ عورتیں اذان نہیں کہہ سکتیں، البتہ نابالغ بچہ کہہ سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ بات بھی بغور سمجھنے کی ہے کہ اِس سے صرف آخرت نہیں بنتی بلکہ دنیا کی صلاح و بربادی بھی نماز کے قیام اور چھوڑ دینے پر منحصر ہے۔
روزہ بھی ویسے فرض ہے جیسے نماز۔ جس طرح کسی کے ادا کرنے سے کسی دوسرے کی نماز نہیں ہوتی، ویسے ہی روزہ بھی بذاتِ خود رکھنا لازم ہے۔ جو روزے چھوٹ گئے ہوں، اُن کی قضا بھی لازم ہے۔ اللہ نے کچھ خاص مواقع کے لیے جو چھوٹ دی ہے، اُسے بہانہ بناکر روزے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔
زکوٰۃ کا مطلب اپنے مال میں سے مخصوص حصے کو نکال کر پھینکنا نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے لیے موقع و محل دیکھنا اور پاکی پلیدی کی جانچ ضروری ہے اور ہر نمازی کے لیے بذاتِ خود ضروری ہے، ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی موقع ڈھونڈنا اور اُس کی جانچ پڑتال کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور بذاتِ خود ضروری ہے۔ سال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ کا حساب فوراً مکمل کرلینا چاہیے اور جب بھی کوئی درست مصرف نظر آئے تو اِس رقم کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ باوجود پوری تلاش کے جب تک درست مصرف نظر نہ آئے، تب تک اِس رقم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے خواہ یہ کتنے ہی دن تک رکھی رہے۔ مالِ زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگوں اور اداروں کے بارے میں کامل اطمینان کے بعد ہی زکوٰۃ اُن کے سپرد کرنی چاہیے کیونکہ اِس کے بعد زکوٰۃ دینے والا فقہی طور پر اِس فرض سے فارغ ہوجاتا ہے اور یہ تحقیق کہ مالِ زکوٰۃ کہاں لگایا گیا، اُس کے ذمے نہیں رہتی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی لوگوں کے مالوں میں برکت اور اُن کے مالوں کی حفاظت اِس لیے نہیں ہوتی کہ اُن کے زکوٰۃ کی مد میں دیے ہوئے پیسے زکوٰۃ کے درست مصرف میں استعمال نہیں ہوتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو جب کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مالِ زکوٰۃ کے درست مصرف میں نہ لگنے سے نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بلکہ مال جیسی نعمت کے غلط مصرف میں لگنے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اِس بارے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا صرف رمضان میں دیا جانا ضروری نہیں۔ پورے سال میں کسی بھی وقت کوئی مستحق نظر آجائے تو اُسے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ایک آسان ترتیب یہ بھی ہے کہ حساب کرلینے کے بعد کل رقم کو بارہ مہینوں پر تقسیم کرکے ہر مہینے ادائیگی کی جاتی رہے۔ یکمشت ادائیگی کبھی کبھی بوجھ بھی بن جاتی ہے۔
زکوٰۃ اِس انداز میں نہیں دینی چاہیے کہ لوگ اِسے اپنا حق سمجھنے لگیں، بلکہ اِسے اِس انداز میں لگانا چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والا آئندہ کے لیے اِس کا مستحق نہ رہے اور خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ مدینہ شہر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا اِس لیے نہیں ملتا تھا کہ اُن لوگوں نے مل جل کر سب ضرورت مندوں کو ایسی ترتیب بناکر زکوٰۃ دی تھی کہ کچھ ہی عرصے میں یہ سب کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگئے تھے۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے خاندان اور محلے کی سطح پر چھوٹے چھوٹے گروپ بنانے چاہییں یعنی کچھ کچھ لوگوں کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے: ضرورت مند خود تلاش کریں اور خود خرچ کریں۔ اِس کی بہترین شکل یہ ہے کہ رشتے دار مل کر ہر بار اپنے کسی قریبی مستحق رشتے دار کو مناسب کاروبار کرادیں، اور اِسی طرح محلے دار، وغیرہ۔ زکوٰۃ کا مال جہاں کے امیروں سے لے کر جمع کیا گیا ہو اُسے اصولًا وہیں کے غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ جو رشتے دار جتنا قریبی ہے، وہ زکوٰۃ کا اُتنا زیادہ مستحق ہے۔ مدارس دینیہ اور سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیرِ تعلیم بے آسرا مسلمان طلبہ و طالبات مالِ زکوٰۃ کا ایک جائز مصرف ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جو اِسے قبول کرے، اُس کا احسان ماننا چاہیے کہ اُس کی وجہ سے آپ اِس فرض کے ادا کرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ بہت جزائے خیر دے ہمارے علمائے کرام کو کہ امت کے اِس بنیادی فرض کی ادائیگی کے لیے سبیلیں پیدا فرماتے رہتے ہیں۔
حج کی فرضیت کی بنیادی شرط اِس سفر کی استطاعت رکھنا ہے یعنی مالی اور بدنی اعتبار سے مضبوط ہونا۔ دوسروں کے ہدیہ کیے ہوئے پیسوں سے حجِ بدل ہوتا ہے نہ کہ حج۔ ہاں! اِس سے فریضۂ حج ادا ہوجاتا ہے اور حج کرنے والے کو زیارات اور عبادات کا اجر بھی ملتا ہے۔ حکومت کے کسی کو حج کرانے کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ حکومت پر نہ تو حج فرض ہے اور نہ حجِ بدل کی کوئی تُک بنتی ہے۔ حج انسانوں پر فرض ہے نہ کہ حکومت پر۔ کوئی مسلم یا غیر مسلم حاکم کسی کو اپنے ذاتی مال سے حج کرادے تو اِسے حکومت کا کرایا ہوا حج نہیں کہیں گے۔ نیز جو حکومت خود قرضے پر چلتی ہو وہ کسی کو حج کیسے کراسکتی ہے؟ اور یہ بات معلوم ہے کہ اِس وقت پوری دنیا کی حکومتیں قرض لے کر کام کرتی ہیں۔ مقروض پر تو حج ویسے ہی فرض نہیں۔ جو لوگ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور مالکِ ادارہ قرعہ اندازی یا نامزدگی کے ذریعے ملازمین کو حج کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے تو کسی کے ذاتی کاروبار کی حد تک تو اِسے یوں درست کہا جاسکتا ہے کہ اُس مالک نے اپنے لیے حجِ بدل کرایا ہے یا حج کے لیے رقم ہدیہ کی ہے، لیکن اگر ادارہ سرکاری ہو تو اجتماعی مال کے ساتھ ایسا حیلہ کرنا بڑی جرات ہے۔ فقہ میں اگرچہ بیت المال کی رقم سے حج کرانے کی اجازت موجود ہے لیکن تقویٰ میں عمومی کمی، مال کے بارے میں للچاؤ، اقربا پروری اور دیگر کئی وجوہ سے یہ عملًا مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کے مال سے حج و عمرہ نہ کیا جائے۔
نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ و مکہ شہروں میں عورتیں بھی دکانداری کرتی تھیں، بلکہ آج تک کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مالِ تجارت لے کر بذاتِ خود سفر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں عورتوں کا ملازمت کرنا اور کاروبار کرنا ہرگز حرام نہیں ہے۔ ہاں! بے پرد ہونا حرام ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو عصری تعلیم اور فنی تربیت دے کر معاشرے کا کارآمد رکن بنانا دورِ جدید کی روشن خیالی نہیں ہے بلکہ ابتدائے نبوت سے اسلام کی تعلیم ہے اور اِن کو عضوِ معطل بناکر گھر ہی میں ڈالے رکھنا دین کے فہم سے عاری ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کی بیٹیاں اور بیویاں گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی ہیں۔ حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خاتونِ جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا اونٹوں کو کھلانے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں پیسا کرتی تھیں اور اناج پیسنے کے لیے چکی چلاتی تھیں، اور اُن کے جسمِ اطہر پر پانی کی مشک مستقلًا لادنے کی وجہ سے نشان پڑگئے تھے۔ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنھیں مخصوص ذکر ’’تسبیحاتِ فاطمہ‘‘ عنایت فرمایا تھا جس سے جسمانی مشقت سے ہونے والی تھکاوٹ دور ہوجاتی ہے۔ یہ ذکر خاص عورتوں کے لیے ہے جس سے مرد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں جو گھریلو صنعت لگاکر کام کرتی تھیں۔ اُن سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص ہر رات میں سورۂ واقعہ پڑھے، اُس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ پوری امت اِن محنتی اور کارگزار خواتین کی احسان مند ہے کہ اِن کی برکت سے امت کو یہ اعمال تعلیم فرمائے گئے۔ امت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا جیسے مسلمان مردوں کے ذمے ہے ویسے ہی مسلمان عورتوں کے بھی ذمے ہے۔
ایسی ہی کچھ غلط فہمیاں استخارہ، اعتکاف، صدقہ و خیرات، لباس، نکاح اور نکاحِ ثانی، عدت، ساس بہو کے جھگڑے کو مذہبی سٹنٹ بنانا، میڈیا اور تصویریت، قرض کی واپسی اور لین دین، اور قومی و ملّی شعائر و شخصیات کے احترام وغیرہ کے بارے میں بھی عام ہیں۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ مشورہ وہی کرتا ہے جس کا معاملہ ہو۔ یاد رکھیے کہ جب حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا تو اُنھوں نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے استخارہ کروں گی۔ آج یہ بات سمجھنے کے لیے بڑے بڑے دین دار بھی تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے اور یہ خاتون خود استخارہ کرنے کا کہتی ہے! یہ اِس لیے تھا کہ اُن لوگوں میں دین کی سمجھ تھی۔ کیا یہ خاتون، ہماری ماں، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا اِس بات سے ناواقف تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے نکلنے والی ہر بات اللہ کی منشا کے مطابق ہوتی ہے اور یہ کہ اُنھوں نے اللہ کے حکم ہی سے اُنھیں اپنا رشتہ بھیجا ہے؟ اِن لوگوں کو دین کی ایسی سمجھ تھی کہ اِس خاتون نے یہ بھی نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہو کہ وہ اُن کے لیے استخارہ فرمادیں۔ اپنے لیے استخارہ اُنھوں نے خود ہی کیا! اُن لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو استخارہ سنٹر بناکر سادہ لوح مسلمانوں کو لوٹتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ گاجریں کوئی کھائے اور پیٹ میں درد کسی اور کے ہو؟ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو ابھی خود شادی شدہ نہیں ہے اور استخارے کے لیے لڑکیوں کی تصویریں جمع کرانے کو کہتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ کسی بزرگ کا تو کیا سوال، لڑکی کے لیے استخارہ تو اُس کے ماں باپ تک نہیں کرسکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی سنت یہ ہے کہ شادی کے لیے استخارہ صاحبین معاملہ یعنی وہ لڑکا اور لڑکی خود کریں جن کا رشتہ ہونے کی بات چل رہی ہے۔ اگر اِن استخارہ کرنے والے لڑکا یا لڑکی کو کوئی اشارہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ اللہ کی جانب سے اُن کے لیے گویا بلینک چیک ہے۔ اِن کے رشتے میں خیر ہی خیر ہوگی، اِس لیے کہ اِن دونوں نے اللہ سے مشورہ کرلیا ہے۔ اور اللہ سے مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا! استخارے کی اِسی فلاسفی کو کاروبار، سفر، وغیرہ کے لیے بلاتکلف استعمال کیا جانا چاہیے۔
اعتکاف ایک مستقل سنت ہے۔ کسی معتکف کے لیے اگر گھر سے کھانا لانے لے جانے والے کا انتظام نہ ہو تو وہ خود کھانا لا اور لے جاسکتا ہے، اِس خدمت کے لیے کسی پر بوجھ بننا اور سوال کرنا ناجائز ہی نہیں بلکہ شدید مکروہ فعل ہے۔ رفعِ حاجت کے لیے گھر میں آیا جاسکتا ہے۔ ہاں! فالتو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے۔ سخت گرمی کے دنوں میں اعتکاف میں بیٹھے لوگوں کو نہانے سے روکنا اور سلام کا جواب تک دینے سے منع کرنا وغیرہ وہ شدتیں ہیں جو تمام بلادِ اسلامیہ میں صرف ہمارے ہاں ہی پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی ایک مسجد میں مکۂ معظمہ کے قدیمی رہائشی کچھ عربوں نے معتکفین کی یہ صورتِ حال دیکھی تو بہت جزبز ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا سر مبارک گھر کے اندر کرکے تیل بھی لگوایا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے سلام دعا بھی یقینًا فرمائی ہوگی۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کی ترغیب دینی چاہیے اور اُن کے لیے اِس کا ماحول بنانا مردوں کے ذمے ہے۔
صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، لیکن اِس کی ادائیگی کے معاملے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں عام طور سے رواج میں ہیں جن سے مکروہ معاشرتی برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ صدقے کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی کو اِتنا مال دے دینا کہ وہ للچا جائے یا غلط فہمی کا شکار ہوجائے، یہ درست نہیں۔ زکوٰۃ کی طرح صدقہ بھی ایک ہی ضرورت مند کو بھی دیا جاسکتا ہے اور تقسیم کرکے کئیوں کو بھی۔ صدقے میں جانور کا ذبح کرنا درست ہے لیکن اِس کے لیے کالے رنگ کے جانور پر اصرار صرف ہم ہندی مسلمانوں کے ہاں ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ہندو اِسے بدشگونی سمجھتے ہیں، مسلمانوں نے شاید اِسی سے کالے رنگ کے جانور کی قربانی کو بدشگونی رفع کرنے کا سبب سمجھ لیا ہے۔ صدقہ روزانہ دینا چاہیے اور اِتنی مقدار میں کہ بوجھ محسوس نہ ہو۔ صدقہ و خیرات کرکے خود قلاش و محتاج ہوجانا بالکل درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے لوگوں کا مال قبول نہیں فرمایا، اور ایسوں کا بھی جو صدقہ و خیرات کرکے احسان جتاتے ہیں۔ صدقے کی حقیر سے حقیر مقدار بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دینا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کے لیے کچھ پڑھ کر اُسے بخش دینا بھی صدقہ ہے۔ ایسا صدقہ جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو صدقۂ جاریہ کہلاتا ہے: مسجد، پل یا تالاب بنوا دینا، کسی کو عالم، حافظ یا قاری بنا دینا، کسی کو عصری تعلیم دلا دینا کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرسکے اور معاشرے کا کارآمد فرد بن سکے، دینی یا دنیاوی علوم کی درسگاہ بنوا دینا، وغیرہ۔
اب لباس کی طرف آئیے۔ اسلام نے لباس کے آداب اور رکھ رکھاؤ (Dress code) دیا ہے نہ کہ فی نفسہٖ کوئی خاص لباس، اور یہ اِس لیے ضروری تھا کہ اسلام نے قیامت تک کے زمانے کے لیے اور دنیا کے گرم و سرد اور بنجر و شاداب ہر علاقے کے لیے اپنے آپ کو قابلِ قبول بنانا تھا۔ بلکہ ایک اِس دنیا ہی کے لیے کیا، جتنے سیارے اِس کے علاوہ ہیں اور جتنے ابھی دریافت ہونے والے ہیں اُن سب میں جہاں جن و انس آباد ہوسکتے ہیں اُن کے لیے مناسبِ حال شرعی پہناووں کا متنوع حل دینا بھی اِس عالمی و فطری مذہب کے لیے ضروری تھا۔ معاشرتی دباؤ اور چلن کی وجہ سے لباس کے بارے میں غیر ضروری شدت بلکہ لباس کو ’’اسلامی‘‘ اور ’’غیر اسلامی‘‘ تک قرار دے دینا ہماری دلچسپ اسلامی حماقتوں میں سے ہے۔ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر دھوتی پہنی، شلوار کبھی نہیں پہنی، اور نہ کبھی شیروانی پہنی۔ ہمارے دین دار لوگ شلوار ہمیشہ اور شیروانی اکثر پہنتے ہیں، لیکن حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی سنت یعنی دھوتی البتہ بالکل نہیں پہنتے۔ اِلّا ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی مانگ کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اِسے دیکھا تھا تو ہی یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ سر کا ڈھکا ہونا ادب بھی ہے اور سنت بھی، لیکن اِسے ٹھیٹھ اسلام اور غیر اسلام کا مسئلہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ سید ذوالکفل مرحوم فرماتے تھے کہ اتباعِ سنت میں ٹوپی ضرور پہننی چاہیے، لیکن اتباعِ سنت ہی میں اِسے کبھی کبھی اتار بھی دینا چاہیے۔ کالر والے کوٹ اور کالر والی یا گول گھیرے والی قمیص کو عیسائیت کا نشان سمجھنا بھی دورِ حاضر کی شدید غلط فہمی ہے؛ لباس کی یہ وضع قطع قدیم مسلمان عمائدین سے لے کر خلافتِ عثمانیہ کے اہلکاروں کے سرکاری لباسوں تک میں ملتی ہے۔ لڑکیوں کو فراک پہنانا بھی برِ عظیم پاک و ہند میں بڑی دیر تک دین باہر ہونے کی علامت رہا ہے کیونکہ یہ لباس فرنگنیں اپنے ساتھ لائی تھیں، حالانکہ معلوم ہے کہ اِس لباس میں پردہ زیادہ ہے۔ پتلون کو ٹھیٹھ فرنگی لباس سمجھنا بھی راہِ اعتدال سے ہٹ جانا ہے؛ حضرت عمر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کی اسلامی فوج کے یونیفارم کی وضع ایسی ہی رہی ہے اور آج تک کی مسلمان افواج میں چلن میں ہے۔ اِسی طرح ٹائی کو صلیب سمجھنا بھی ایک دیرینہ اسلامی لطیفہ رہا ہے۔ المختصر ضرورت کے وقت ایسے پہناوے استعمال کرلینے والے مسلمانوں کے بارے میں دل برا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں یہ اور ایسے لباس اب عام شہری اور دفتری چلن میں ہیں۔ خلاصۂ کلام یہ کہ کوئی لباس اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتا؛ جس جگہ کے مہذب مسلمان جو لباس عام طور سے اختیار کرلیں وہی وہاں کا عام مذہبی لباس ہے۔
عورتوں کے لباس کی اسلامائزیشن کے بارے میں بھی ایسی ہی کئی غلط فہمیاں ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پردہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور مسلمان عورتوں کا امتیازی نشان، اور برقع پردہ کرنے کے لباسوں میں سے ایک لباس ہے۔ لہٰذا موقع و محل کے مطابق پردے کے لیے برقع یا کوئی اور لباس یعنی چادر وغیرہ استعمال کی جاسکتی ہے۔ برقعے کی کوئی بھی وضع قطع مسنون نہیں ہے۔ ٹوپی والا تو برقع تو خالص ہمارے علاقے کی ایک ڈیڑھ صدی پہلے کی ایجاد بلکہ بدعتِ حسنہ ہے۔ جب اِس میں شدت کی گئی تو اِس کے لازمی ردِ عمل کے طور پر ایسے برقعے نظر آنے لگے جو اِتنے جاذبِ نظر اور چست ہوتے ہیں کہ پہنے ہی اِس لیے جاتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو بار بار دیکھے، بلکہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے۔ پہلی نظر معاف ہے؛ یہ پہلی نظر اگر ختم ہو تو دوسری کی باری آئے۔ یعنی برقعے کا مقصد ہی فوت ہوگیا۔ نیز کئی صورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر برقع نہ پہنیں تو اُنھیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ چنانچہ ایسا برقع ہی داعیِ گناہ بن جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جس برقعے یعنی بڑی چادر کا ذکر احادیثِ پاک میں ملتا ہے اُس وضع قطع والا پہناوا وہ ہے جو آج عبایا کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ایران، عراق، شام و فلسطین وغیرہ میں عام رواج میں ہے۔ میں ایک بار سید ذوالکفل مرحوم کے ساتھ ایک اسلامی ملک کے سفارت خانے میں گیا جہاں کے عملے میں ایک برقعے والی پاکستانی لڑکی بھی تھی اور دفتری کوٹ کے ساتھ گھٹنوں تک سکرٹ پہنے ہوئے ادھ ننگی ٹانگوں والی کچھ انگریزنیاں بھی۔ بھائی ذوالکفل نے چھوٹتے ہی کہا کہ اِس برقعے والی جھانپو کبوتری کو دیکھ کر وہ حدیث پاک یاد آئی کہ کچھ عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ بات چلی تو مزید فرمایا کہ دفتر میں کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کو یونیفارم کی طرح کا کوئی مخصوص دفتری لباس پہننے کی پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اِس سے بہت حفاظت رہتی ہے۔
عورتوں کو برقعے میں اِتنا چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ اُنھیں پہچانا ہی نہ جاسکے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ برقعے کا مقصد زینت کو چھپانا ہے نہ کہ عورت کی شناخت کو چھپانا۔ شناخت کو چھپانا شرعًا اور قانونًا جرم ہے، اور خصوصًا آج کے حالات میں تو اپنی شناخت لازمًا خود ہی کرانی چاہیے۔ لیکن اِس سب بحث سے عورتوں کے لیے پورے جسم خصوصًا چہرے کا پردہ نہ کرنے کا جواز نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ پردے کا حکم بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ ہے۔ اللہ کے احکامات قیامت تک تبدیل نہیں ہوں گے۔ حیا مسلمان کا زیور ہے اور برقع و چادر مسلمان عورتوں کے لیے اِس کا ظاہری لباس ہے، چنانچہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اِس پر کسی حال میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ بہت جزائے خیر دے ہماری اُن خواتین کو جنھوں نے دین کے اِس شعیرہ کو زندہ رکھا ہے۔
اگلی بات نکاح و شادی سے متعلق ہے۔ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین حلقے کے ایک مالدار ترین صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک روز خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو کپڑوں پر کچھ زعفران کا سا رنگ تھا جیسا کہ اُس دور میں شادی کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمیں بلایا ہوتا تو ہم بھی آپ کی شادی میں شرکت کرتے۔ معلوم ہوا کہ شادی کرنا اُس دور میں اِس قدر آسان ہوگیا تھا اور اِس کو کوئی ایسا موقع تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ ضرور ہی ساری برادری اور سبھی اہم لوگوں کو جمع کیا جائے۔ شادی کا اعلان ضروری ہے نہ سب کو جمع کرنا، کئی کئی روز تک پرتکلف کھانے کھلانا اور پوری برادری میں جوڑے بانٹنا۔ رسموں کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے میں پڑجانے کی وجہ سے ہم لوگوں نے شادی کو خاندان کی معاشی موت بنا دیا ہے۔ عربستان میں نکاحِ مسیار کا مسئلہ اِنہی رواجی خرچوں کو درجۂ اسلام تک پہنچا دینے کی شدت کا لازمی نتیجہ ہے جو ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں نے عفت اور فطرت کی زندگی گزارنے کے لیے تنگ آکر شروع کیا ہے۔ کیا معلوم کچھ عرصے میں یہ ’’بغاوت‘‘ ہمارے ہاں بھی ہوجائے۔ نکاح اور شادی دو الگ الگ چیزیں ہیں: نکاح کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور شادی یعنی اِس موقع کی خوشی کو اپنے رواج، آسودگی اور سہولت کے مطابق اسراف سے بچتے ہوئے سادگی سے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر شادی یعنی نکاح کے موقع کی خوشی کو بڑے پیمانے پر منانے کی استطاعت نہ ہو تو اِس کی وجہ سے نکاح کو موخر نہ کرنا چاہیے۔ اگر اِن دونوں مواقع کو ایک دوسرے سے ذرا سا الگ کرکے کرنے کا رواج بنا لیا جائے تو بہت سہولتیں ہوسکتی ہیں اور سفید پوشی کا بھرم رہ سکتا ہے۔ اور اِس کے ذیلی نتائج میں گھر بیٹھی بوڑھی ہوتی لڑکیوں کو پرنانے کے مسئلے کا آسان حل بھی پوشیدہ ہے۔
وقت پر شادی نہ ہونے کی اُتنی بڑی وجہ معاشی ناآسودگی نہیں ہے جتنی کہ ذات برادری۔ اِسے کیا کیجیے کہ ذات برادری کے خالصتًا رواجی چکر کو بھی مذہب کی حمایت عطا کردی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اُن کی اتباع میں سبھی صاحبِ استطاعت صحابہ کرام نے خود مختلف خاندانوں میں شادیاں کرکے اور برادری باہر والوں میں اپنی بیٹیاں اور بہنیں دے کر اِس جہلِ مرکب کو ختم کرنے میں اپنا شاندار کردار ادا فرما دیا ہے۔ ہم میں سے کسی کی بیٹی نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ عالی خاندان کی نہیں ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں باہر دی ہیں، لہٰذا بیٹی خاندان سے باہر دینا سنت بھی ہے۔ خاندان باہر والوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اِتنے راضی تھے کہ فرمایا کہ اگر میری سو بیٹیاں بھی ہوتیں تو بیاہ دیتا۔ اوروں کا تو کیا ذکر، افسوس اِس پر ہے کہ آج پاکستان و ہندوستان میں سید ہی وہ لوگ ہیں جو اِس سنت کو پوری قوت کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں، چنانچہ اِن کی دیکھا دیکھی ارائیں، جٹ، راجپوت، اعوان، وغیرہ بھی خاندانی عصبیت کی اِسی رو میں بہہ نکلے ہیں۔ اِس (ظاہراً) نابرابری کے مسئلے کو مستقبل میں بڑھتا دیکھ کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ خود سید تھے، لکھا تھا کہ ہندوستان میں راجپوت سیدوں کے کفو یعنی برابر ہیں (اُس وقت میں یہاں بڑی راجدھانیاں راجپوتوں کی تھیں)۔ بین الخاندانی، بین البرادری، بین المللی اور بین الثقافتی شادیوں میں قومی، صوبائی، لسانی وغیرہ منافرتوں کا جڑ سے اکھیڑ دینا بھی پنہاں ہے، اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں تو شادیوں سے یہ کام بطورِ خاص لیا گیا ہے۔ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں نے نکاح سے زیادہ کسی چیز کو جوڑنے والا نہیں پایا۔ چنانچہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ رشتہ تلاش کرتے وقت معاشی، سماجی، ذہنی و تعلیمی، جسمانی اور صحت وغیرہ کے اعتبارات سے برابری کو پہلے دیکھا جائے اور صرف برادری ہی پر اصرار نہ کیا جائے۔ ہمارا عمومی حال یہ ہے کہ ہم برابری سے مراد صرف برادری لیتے ہیں، اور نتیجۃً بچوں بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔
برابری کا دیکھا جانا کتنا ضروری ہے، اِس کے لیے یہی مثال دینا کافی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق سماجی نابرابری کی وجہ سے دلوائی تھی کیونکہ اِس عالی خاندان آزاد خاتون کا نکاح غلام مرد سے ہوا تھا۔ خاندان برادری کی اکڑ کے ساتھ ساتھ ایک شدید غلط فہمی دین داری اور تعلیم کے معاملے میں بھی ہے۔ بیٹیوں کے لیے کسی حسن بصری کے انتظار میں اور بیٹوں کے لیے رابعہ بصری کے انتظار میں اولاد کو بٹھائے رکھنا اور شادی کی عمر گزار دینا کہاں کا اسلام ہے؟ ہم ذرا سے کم پر کیوں راضی نہیں ہوجاتے؟ کیا ہم خود ہر کمی سے پاک ہیں؟ کیا ایک مسلمان لڑکا یا لڑکی جو آج ذرا سا کم دین دار ہے، کسی نسبۃً زیادہ دین دار خاندان میں شادی ہونے کی برکت سے بہتر مسلمان بننے کا امکان نہیں رکھتا؟ نیز اگر بیٹی زیادہ پڑھی لکھی ہے تو کیا نسبۃً کم پڑھا لکھا لڑکا نہیں چل سکتا؟ اور اگر ڈگری کی برابری کے بغیر رشتہ نہیں سِرتا تو کیا لڑکے کے شادی کے بعد تعلیم جاری رکھے رکھنے پر کوئی شرعی یا قانونی پابندی ہے؟ ذات برادری کے ساتھ ساتھ جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ اور جائیداد کا چتھیرا جانا بھی لڑکیوں کو بٹھائے رکھنے کا سبب ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کہ برِ عظیم پاک و ہند کے کچھ علاقوں میں لڑکی کا نکاح مرغے کے ساتھ اور کہیں قرآن کے ساتھ کردیا جاتا ہے۔ اِس مذاق کا اسلام جیسے فطری مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے اِس کے کہ یہ مذاق کرنے والے مسلمان ہیں!
اِس وقت عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہوچکی ہے۔ ساری دنیا کے چلن دار مذاہب میں اِس گمبھیر مسئلے کا حل صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ اسلام کے فطری مذہب ہونے کی ایک زندہ علامت ہے کہ اِس کے پاس ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے۔ موت فوت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یورپ و امریکہ اور بہتیرے بلادِ اسلامیہ کے مسلمانوں میں طلاق یافتہ یا بیوہ لڑکی کی دوسری شادی میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے ماحول کی وجہ سے ایسے سانحات کو لازمی سماجی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی پیش آسکتا ہے، چنانچہ ایسے سانحات کا شکار لڑکیوں کو منحوس یا دوسرے درجے کا شہری تصور نہیں کیا جاتا جیسا کہ ہمارے ہاں عام ہے۔ غضب خدا کا، میں نے ایک نئی شادی شدہ لڑکی اور اُس کی ماں کو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان بیوہ کے ہاں تعزیت کے لیے جانے سے گریزاں تھیں، اور جب مارے باندھے چلی ہی گئیں تو اُس بے چاری کے پیش کردہ گلاس ہاتھ میں پکڑنے سے انکاری تھیں۔ بالآخر اُن کی مہمانداری خاندان کی ایک اور خاتون نے کی۔ ہندوؤں کے سماجی اثرات کو قبول کرتے کرتے ہم ہندی مسلمان یہاں تک تو آگئے ہیں کہ اچھے بھلے دین دار لوگ بھی بیوہ/ طلاق یافتہ لڑکی کو منحوس جانتے ہیں، چنانچہ اُس کی دوسری شادی کا تو کیا سوال۔ کیا معلوم ہندو عورتوں میں ستی ہوجانا اِسی لیے شروع ہوا ہو کہ خاوند کے بعد دھتکاریں نہ پڑیں کیونکہ کسی اور سے تو شادی ہو نہیں سکتی۔ ہم مسلمانوں کی ایسے سانحے سے گزری ہوئی لڑکیاں زندگی کی آخری سانس تک زندہ ستی ہوتی رہتی ہیں۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اسلام کے ہندوستانی ورژن کی بجائے اصل ورژن پر عمل کرنے کو لازم پکڑیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی کم و بیش چھے (۶) شادیاں ہوئیں۔ اِن پے در پے شادیوں کے باوجود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمیت کسی کی ناک نہیں کٹی اور نہ ہی یہ محترم خاتون کبھی نشانۂ تعریض بنیں۔ کیا ہماری بیوہ بہنیں بیٹیاں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے زیادہ محترم ہیں، یا خاکم بدہن ہم یارؐ اور یارِ غارؓ سے زیادہ غیور ہیں؟ بیوہ یا مطلقہ کسی بھی عمر کی ہوں، اُن کو فارغ نہ رکھنا اور عدت و سوگ کا زمانہ ختم ہوتے ہی جلد سے جلد دوبارہ بیاہ دینا، بلکہ عدت کے اندر ہی سلسلۂ جنبانی شروع کردینے میں بھی کوئی عیب نہ سمجھنا، وہاں کے معاشرتی رواج میں لے آیا گیا تھا۔ اِس میں بڑی بچت ہے، کیونکہ یہ عینِ فطرت ہے۔
کنوار پنے کی نسبت رنڈاپا پاکبازی سے گزارنا زیادہ مشکل ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ کھلی آنکھوں سے اِرد گرد کے حالات پر ذرا غور کیجیے تو معلوم ہوجاتا ہے کہ فقہ میں زنانِ شوہر دیدہ کے لیے احکامات مختلف کیوں ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیادہ شادیاں کرکے اور اُن کی اتباع میں حضرات صحابہ کرام نے بھی ایسا کرکے اسلام کے ابتدائی دنوں میں وہ صورت بنادی تھی کہ پورے شہر اور خاندان میں کوئی عورت خالی نہ رہتی تھی۔ اُس معاشرے میں ہر عورت کے سر کا سائیں ضرور ہوتا تھا اور کوئی عورت گواچی گائے کی طرح نہیں پھرتی تھی۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہاں نہ صرف پردے پردے بدکاری بلکہ پیشہ ورانہ بدکاری بھی کم سے کم ہوتی گئی اور نکاح آسان سے آسان ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک صحابی دوسرے کو اپنا وکیل بناکر ایک گھر میں پیغام دے کر بھیجتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو اُس وکیل ہی کو قبول کرلیا گیا ہوتا ہے، اور اِس پر اِن دونوں میں کوئی شکر رنجی نہیں ہوتی۔ اِس فطری انسانی ضرورت کی پکار پر ہاں کہتے ہوئے کچھ مسلم معاشروں میں یہ رواج رہا ہے کہ وہاں رہنے کے لیے ہر مرد کو شادی کرنا لازم ہوتا تھا۔ بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کی شادی کے ضمن میں اگر ہماری عورتیں ذرا سا دل بڑا کرلیں اور اتباعِ سنت میں دوسری بہن کو برداشت کرنا سیکھ لیں تو یہ مسئلہ مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ الغرض اگر نکاح کو آسان بنایا جائے اور نکاحِ ثانی والی منشائے دین محمدی کو رواج میں لانے کی سنجیدہ کوشش کی جائے تو جہاں تاعمر غیر فطری زندگی گزارنے، جنسی و سماجی گھٹن، لوگوں کی نگاہوں میں ہمدردی کے تکلیف دہ پیغام پڑھنے، کنواریوں اور سہاگنوں کو اپنی پرچھاؤں سے بچتے پانے، اور طرح طرح کے گناہوں اور بدکاری میں کمی ہوگی وہاں معاشرے میں بحیثیت مجموعی معاشی ترقی بھی ہوگی کیونکہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نکاح سے معاشی آسودگی ملتی ہے، اور اگر ایک نکاح سے نہیں ملتی تو دوسرا نکاح کرنا چاہیے اور اِسی طرح تیسرا۔ ہاں! نکاحِ ثانی کا مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے ادھیڑ عمر کے مرد دیکھے ہیں جو بیوی کے داغِ مفارقت دے جانے یا کسی لاعلاج مرض کا شکار ہوجانے کے بعد سماجی دباؤ کی وجہ سے ساری زندگی رِس رِس کر گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی ہندوؤں کے سماجی اثرات قبول کرنے کا نتیجہ ہے۔
ایک ایسا ہی مسئلہ عدت کا ہے جس کی شرح میں ہر عیسیٰ کا اپنا دین ہے اور ہر موسیٰ کا اپنا۔ کسی خاتون کا شوہر فوت ہوجائے تو جہاں وہ بے آسرا ہوجاتی ہے، وہاں کئی رشتے دار بھی اُس کا خیال رکھنے کے اسلامی حکم کی کچھ ایسی تاویلات کرتے ہیں کہ خاکم بدہن عدت کے مسائل کا پتھراؤ شروع کردیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عدت الگ حکم ہے اور خاوند کا سوگ الگ۔ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مغالطہ بڑے بڑوں کو لگا ہوا ہے کہ عدت اور سوگ ایک ہی چیز ہیں۔ عدت کی مدت وضعِ حمل تک ہے جس کا مقصد حمل کی تحقیق ہے۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی یا حمل کے کسی بھی وقت گر جانے سے عدت فوراً ختم ہوجاتی ہے، سوگ البتہ باقی رہتا ہے۔ جس عورت کی بچہ دانی آپریشن کرکے نکالی جاچکی ہو، اُس کی عدت صرف سوگ ہے، کیونکہ جب محل حمل ہی موجود نہیں تو حمل کی تحقیق کا کیا سوال۔ اور سوگ کا مطلب اور مقصد بھی بے جا آرائش سے گریز ہے نہ کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہنا اور کنگھی تیل تک نہ کرنا۔ عدت کے اندر بھی عورت ضروری سفر کرسکتی ہے اور جتنی بار ضروری ہو اُتنی بار کرسکتی ہے، مثلًا ڈاکٹر کے ہاں جانا، یا مثلًا جس دفتر یا بنک میں حاضری ضروری ہو وہاں جانا جیسے پنشن وغیرہ سے متعلق امور میں۔ مختصراً یہ کہ جہاں جانا شرعًا یا قانونًا ضروری ہو، وہاں دورانِ عدت و سوگ بھی آیا جایا جاسکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دورانِ عدت سفر کی اِس شرعی چھوٹ کو رسمی تقریبات وغیرہ میں جاکر مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ نیز اگر یہ بیوہ خود ملازمت کرتی ہے اور اِس کا دفتر عدت کے پورے سوا چار مہینے کی چھٹی نہیں دیتا تو اِسے دفتر کے قانون سے ٹکرانے کی شرعًا اجازت صرف اِسی صورت میں ہے کہ روزی روٹی کی محتاجی نہ ہوجائے۔ ہمارے معاشرے میں عدت اور سوگ دونوں کو بے چاری بیوہ کی مسکینی کے بقدر گاڑھا کیا جاتا رہتا ہے اور اِن میں ایسی ایسی موشگافیاں کی جاتی ہیں کہ بیوہ عملًا ایک اچھوت اور بوجھ بلکہ نشانِ عبرت بن کر رہ جاتی ہے۔
ساس بہو اور نندوں کا جھگڑا بھی ہمارا خالص ہندوستانی سماجیات کا مسئلہ ہے جسے بوجوہ مذہب کی سان پر چڑھاکر اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ اسلام کے آغاز میں اِس مسئلے کا وجود ہی نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بلادِ عرب میں بلکہ آس پاس کے سبھی علاقوں کی ثقافتوں میں شادی کرتے ہی لڑکا لڑکی کو الگ کردیا جاتا تھا (اور ہے)۔ اِس میں شک نہیں کہ عورتوں کے دین کا بہت بڑا حصہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، لیکن ذرا توجہ سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اِس سب ذخیرۂ حدیثِ پاک میں ساس بہو سے متعلق ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، کہ اُن کو کبھی ساس سے واسطہ ہی نہ پڑا تھا۔ چنانچہ ساس بہو کے جھگڑوں سے نبٹنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ سب کی سب استنباطی ہیں نہ کہ دینی۔ حدیثیں اور آیتیں جوڑ کر اُنھیں ساس کی عزت کے لیے استعمال کرانا نہایت درجہ کی جرات ہے۔ لڑکی کو لڑکے کے لیے بیاہ کر لایا جاتا ہے نہ کہ لڑکے کے گھر والوں کے لیے، اور خصوصًا ساس صاحبہ کی ’’خدمت‘‘ کے لیے۔ گھر کے سب لوگوں کے کام کرنا ہرگز لڑکی کے ذمے نہیں ہے، نہ شرعًا نہ اخلاقًا۔ وہ اگر کوئی ذمہ داری لیتی ہے تو یہ اُس کا احسان ہے۔ اللہ نے تو عورت کے لیے بچے کو دودھ تک پلانا لازم نہیں کیا۔
گھر میں جھگڑا اِس بنیادی بات یعنی حقوق و فرائض کی طرف توجہ نہ دینے سے شروع ہوتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے اخلاق و مروت اور شرم و حیا کی سب حدوں کو ملیا میٹ کردیتا ہے۔ لڑکی کا گھر اجاڑنے میں (اُس کی اپنی ماں کے بعد) ساس کے علاوہ شاید ہی کوئی عورت وجہ بنتی ہو، کیونکہ اُسی کو اِس نئی لڑکی کی آمد سے اپنا راج سنگھاسن ڈولتا محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ گھر میں جھگڑوں کی وجہ بڑے بنتے ہیں نہ کہ چھوٹے۔ گھر میں بڑے اگر بڑا بن کر رہیں تو چھوٹوں کے چھوٹا بن کر رہنے کا راستہ ہموار ہوسکتا ہے، اور اِس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر چلیں نہ کہ رواج پر۔ اور جیسا کہ اوپر کی گفتگو سے معلوم ہوا، دینِ اسلام میں خالص ہندی اصطلاح میں ’’مشترک خاندان‘‘ کا ہرگز کوئی تصور نہیں ہے۔ اِس بات کو صاف لفظوں میں لکھنا ضروری ہے کہ میں یہاں خاندانی نظام کے خلاف بات نہیں کر رہا جو ہم ہندوستان و پاکستان والوں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ خاندانوں کی ’’دولتِ مشترکہ‘‘ (Union) کے تصور کی بات کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے یونٹ مل کر ایک دوسرے کے لیے زیادہ کارآمد اور قابلِ قبول ہوسکتے ہیں نہ کہ ایک بڑا گھر جہاں کے مکینوں کو صرف دیواروں نے ایک جگہ جمع کیا ہوا ہو! ’’مشترک خاندان‘‘ کی صورت میں رہنے میں پردے کا حکم بھی ٹوٹتا ہے۔ پورے پاکستان میں گنتی کے چند گھر ہوں گے جہاں شرعی پردہ ہوگا؛ اور اِن میں کے کچھ گھروں کو میں جانتا ہوں کہ مشترک خاندان ہونے کی وجہ سے پردے کی یہ صورت مکینوں کے لیے وبالِ جان بنی ہوئی ہے اور آئے دن کے جھگڑوں کی وجہ سے نوبت بغاوت تک آپہنچی ہے۔
یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ گھروں میں جھگڑوں کی اُتنی بڑی وجہ معاشی ناآسودگی اور سماجی ناہمواری نہیں ہے جتنی کہ بڑے چھوٹے کا لحاظ ملاحظہ نہ کرنا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ ہم اولاد سے تو اکرام و احترام چاہتے ہیں، خود اُن کا اکرام کرنے میں البتہ کمی کرتے ہیں۔ بچوں کو بلاوجہ اِدھر اُدھر دوڑاتے پھراتے ہلکان کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں! ماں باپ اپنے بچوں سے روزانہ ایسی جسمانی خدمت ضرور لیا کریں کہ اُن کے لیے اپنے گھر کا/ کی ہونے کے بعد یہ بوجھ محسوس نہ ہو بلکہ اِس میں وہ اپنی سعادت جانیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن حدیثِ پاک ہی میں باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ خاوند کا لغوی معنی ہی خدا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ خاوند بلائے تو عورت کے لیے نماز جیسی عبادت کو مختصر کرکے اور اگر نفل پڑھ رہی ہو تو نیت توڑ کر جانے کا حکم ہے۔ عورت کی ہر نفلی عبادت یہاں تک کہ روزہ بھی خاوند کی اجازت پر موقوف ہے۔ یہ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں۔ اب ایک نظر اپنے اِردگرد دوڑائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ میڈیا کے شور شرابے سے صنفی مساوات کے بہکاوے میں آکر مسلمان معاشرے کا یہ بنیادی یونٹ یعنی خاندان شدید ابتری کا شکار ہوچکا ہے۔ لڑکیوں کو خاوندوں کی عزت کرنا سکھانا ماؤں کے ذمے ہے، اور ظاہر ہے کہ لڑکیاں یہ کرداری خوبی اپنی ماؤں کے ذاتی عمل سے روزانہ کی بنیاد پر سیکھتی ہیں۔ چنانچہ اگر اپنے ذاتی عمل سے بڑے چھوٹے کی تمیز سکھا دی جائے تو یہ مسئلہ مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تمیز کوئی ٹیکہ نہیں ہے جسے لگا دینے سے بچے بچی کی رگوں میں تمیز داری دوڑنے لگے؛ یہ بڑی توجہ سے اور مستقل کرنے کا کام ہے جس میں خاندان کے بڑوں کا اپنا دیرینہ عمل ہی اصل محرک اور مثالی نمونہ ہوتا ہے۔
تصویر اور میڈیا کے ناجائز ہونے کے بارے میں ایک طرف اِتنا غلو کیا گیا اور دوسری طرف اِتنی آزادی برتی گئی ہے کہ اب تو اِس پر سنجیدگی سے کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ ابھی تو اُن پاک نفس علما کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں جو سرے سے اخبار ہی پڑھنے کے قائل نہ تھے، کہ اِن سے جھوٹ اور غیبت کی اشاعت ہوتی ہے اور تجسس۔ آج کیا ٹی وی اور انٹرنیٹ، اور کیا اخبار کا رنگین صفحہ، لگتا ہے کہ تشہیر کا کوئی بھی ذریعہ اب ویسا حرام نہیں رہا جیسا کہ اب سے صرف دس سال پہلے تک ہوتا تھا۔ مذہبی مکالمہ ہو، سماجی و سیاسی مباحثہ ہو، پریس کانفرنس ہو یا انٹرویو، اِس کے لیے میک اپ کے ساتھ کیمرے کی روشنیوں میں بیٹھنا آج بہت سے لوگ جائز سمجھنے لگے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں کے بڑوں نے ایک پیڑھی پہلے کے علماء کی تقریریں سن کر ٹی وی سیٹ توڑ ڈالے تھے۔ القصہ تصویر جہاں ضروری ہو وہاں اتروانی چاہیے، اور اِس کو اسلام اور غیرِ اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ جامعہ الازہر، سعودی محکمۂ افتاء اور پاکستان کے بڑے دار ہائے اِفتا نے سکیورٹی وجوہات کی وجہ سے سکیورٹی کیمروں کے سامنے مرد و عورت دونوں کے لیے پورا چہرہ کھول کر اور آنکھیں چار کرکے تصویر بنوانے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ اللہ پاک حضرات مفتیانِ کرام کو بہت جزائے خیر دے کہ اِن کی بدولت امت کا بڑا حصہ احساسِ گناہ کے ساتھ جیے جانے کے بوجھ سے آزاد ہوا۔ محتاط علما کے نزدیک تعلیم و تربیت کے مقاصد کے لیے میڈیا، تصویر یا ویڈیو استعمال کرلینے میں کوئی حرج نہیں۔ عوامی اکٹھ کی جگہوں، دفاتر، مساجد اور گھروں وغیرہ میں حفاظتی کیمرے لگانے اور اِن سے لوگوں کے علم میں لائے بغیر اُن کی حرکات و سکنات دیکھنا اور ریکارڈ کرنا بھی فتوتًا درست ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تصویر اور ویڈیو کی یہ اور ایسی سب صورتیں ضرورتِ حادثہ کی پیداوار ہیں۔ فتوے کا مطلب حرام کو حلال کرنا نہیں ہوتا، لہٰذا بدلتے حالات کی وجہ سے تصویر کے لیے دی گئی اِس شرعی چھوٹ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ جو علماء تشہیریت کے لیے تصویر کے معاملے میں آزادہ روی میں بہت آگے چلے گئے ہیں اُن کو مثال بناکر چلنے کی بجائے علماء کے دوسرے طبقے کو قابلِ تقلید جاننا زیادہ بہتر ہے۔
ایک بڑا مسئلہ کرنسی کی قدر و قیمت کا ہے۔ ایک صاحب نے آپ سے کچھ روپے قرض لیے۔ جب وہ واپس کرتے ہیں تو اِن کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو لیتے وقت تھی۔ کیونکہ نوٹ اصل مال نہیں ہے بلکہ مال کی رسید ہے، اِس لیے رقم کی واپسی کے وقت مال کو پورا ہونا چاہیے نہ کہ رسیدوں پر لکھے ہندسوں کو۔ خوب یاد رکھیے کہ رقم کے (خصوصًا لمبی مدت کے لیے کیے گئے) لین دین میں کسی ایسی چیز کو معیار بنائیے جو متوازن رہتی ہو اور اُس کی قدر کم نہ ہوتی ہو، مثلًا سونا، گندم یا چاول، یا مثلًا ڈالر، یورو، پاؤنڈ یا ریال وغیرہ۔ چنانچہ یہ لین دین یوں ہونا چاہیے کہ مثلًا آج اِتنے تولہ سونے/ اِتنے من گندم یا چاول/ اِتنے ڈالر/ یورو/ پاؤنڈ/ ریال کی قیمت پاکستانی روپوں میں قرض لی، اِسے جب ادا کروں گا تو اِتنے ہی تولہ سونے/ اِتنے من گندم یا چاول/ اِتنے ڈالر/ یورو/ پاؤنڈ/ ریال کی قیمت اُس وقت کے مطابق پاکستانی روپوں میں دوں گا۔ علیٰ ہٰذا۔ جن لوگوں نے دوسروں کے پیسے دبا رکھے ہیں اُنھیں اگر واپسی کی توفیق ہوجائے تو اصل مالیت واپس کرنی چاہیے نہ کہ نوٹوں پر لکھے ہوئے ہندسوں کی تعداد کو پورا کرنا، ورنہ اللہ کی میزان میں تو ہر تول پورا کر ہی دیا جائے گا۔
میرے بچپن کی بات ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کو ایک مذہبی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور لے جایا گیا۔ مینارِ پاکستان والے پارک میں جلسہ ہوا۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ نماز بادشاہی مسجد میں جاکر پڑھنی چاہیے۔ وہ بمشکل راضی ہوئے۔ ہم علامہ اقبال کے مزار کے سامنے پہنچے تو اذان شروع ہورہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں فاتحہ بھی پڑھتے چلتے ہیں۔ اِس پر ماسٹر صاحب نے، جو ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے جو پاکستان بنانے کے ’’گناہ‘‘ میں شریک نہ تھیں، اقبال کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہمارے کانوں میں انڈیلیں۔ قصہ کوتاہ، میں اور میرے ساتھ تقریبًا سارے ہی بچے اُن کی حکم عدولی کرتے ہوئے اندر جاکر فاتحہ پڑھ آئے۔
میں ٹوٹا پھوٹا سہی لیکن بحمداللہ مسلمان ہوں۔ میں پاکستانی ہوں۔ وطن کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے (یہ ایک حدیثِ پاک کے الفاظ ہیں)۔ میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں تو مجھے اپنا وطن یاد آتا ہے، اور میں اتباعِ سنت میں اپنے وطن کو یاد کرتا ہوں۔ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ایک جغرافیہ ہے، ایک ثقافت ہے۔ مجھے اِس سب پر فخر ہے، اِس لیے کہ یہ سب میرا اپنا ہے۔ وطن عزیز پاکستان نے اپنے بہت سے قومی وسائل مجھ پر اور میرے خاندان پر خرچ کیے ہیں۔ پاکستان اگر مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی کچھ جماعتوں کے مزاج اور توقعات کے مطابق نہیں بنا ہے تو اِس پر میں کیا کرسکتا ہوں۔ واللہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ سیاسی اختلاف رکھنے والا کلمہ گو ’’کافر‘‘ کیسے ہوجاتا ہے۔ سید القوم سر سید احمد خان، مولانا حالی، سر آغا خان، ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال اور قائدِ اعظم محمد علی جناح وغیرہ ہماری قومی و ملّی تاریخ کے ڈیڑھ ہزار سالہ سفر میں آنے والی تابناک کہکشاؤں میں سے چند بڑے نام ہیں۔ یہ وہ مردانِ راہ داں ہیں جو ستاروں کے لیے نشاناتِ راہ ہیں اور جن کی مختلف جہتوں میں کی گئی سنجیدہ اور پیہم کوششوں سے مسلمانانِ ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ اِن دور اندیش اور دردمند لوگوں نے اُن شاطر انگریزوں کی بچھائی ہوئی بساط پر اُنھیں ہراکر ہم درماندہ مسلمانوں کے لیے آزادی چھینی تھی جو قال اللہ قال الرسول پڑھنے پڑھانے والے ہمارے بڑوں کو توپ سے باندھ کر اُڑا دیا کرتے تھے یا کالا پانی بھیج کر اُنھیں موت کی دعائیں مانگنے میں لگا دیا کرتے تھے۔
آج کچھ لوگ مذہبی و سیاسی آزادی اور وطنی تشخص کو اُس وقت کی غلامی کے مقابلے میں ہلکا جانتے ہیں، یہ نری سادہ خیالی ہے اور حقائق سے فراریت۔ جن لوگوں نے بھی جس جس دور میں اقبال شکنی، جناح شکنی یا سرسید شکنی کی کوششیں کی ہیں یا اِن لوگوں کو کافر کہا ہے، وہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ آج اُن کی کیا عزت ہے؟ بلکہ اُن کو آج جانتا کون ہے؟ یہ اور اِس قبیل (Profile) کے بڑے لوگ کارواں ران ہوتے ہیں۔ جو اِن کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، منزل پاجاتا ہے اور جو اِن کے منہ کو آتا ہے، وہ کارواں سے ٹوٹ جاتا ہے اور جلد ہی اِدھر اُدھر ٹکراکر تھک جاتا ہے۔ ایسے لوگ جنھیں اللہ نے عزت دی ہو، اگر کسی خاص دینی مسلک یا سیاسی مشرب پر نہ ہوں تو بھی اِنھیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اِس غلیظ گوئی سے ایسے ہیاکل کی عزت اور مرتبہ کم نہیں ہوا کرتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اِن کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ یہ ذکر کردہ لوگ تقویٰ طہارت اور عقائد کے اعتبار سے کیسے بھی کمزور ہوں، بہرحال مسلمان ہیں، اور برِ عظیم کی قومی و ملّی تاریخ کے شدید ہیجانی دور میں شاندار قائدانہ کردار ادا کرگئے ہیں۔ اِس کرداری وصف کی بدولت اللہ نے اِنھیں عمومی نیک نامی اور عوامی مقبولیت عطا فرما دی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ جییں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عزت داروں اور سرداروں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ اُن کی حیثیت اور مرتبے کو دین کی بہتری اور ترویج کے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ ہمیں اِس کی سمجھ دے۔
اِسی طرح عوام میں بہت سی غلط فہمیاں عالمی طور پر پھیلانے والا ایک نیٹ ورک ای میل اور موبائل فون پر بھیجے جانے والے سندیسچے یعنی ایس ایم ایس ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام کا کوئی وظیفہ دس یا پچاس لوگوں کو فارورڈ کرنے سے دس دن میں کوئی خوش خبری نہیں ملتی اور اِسے نہ بھیجنے سے کوئی آفت نہیں آتی۔ کسی اسلامی مہینے کی مبارک باد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی۔ کسی ایس ایم ایس کو فارورڈ کرانے کے لیے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دینا نہایت درجے کی کم قسمتی ہے۔ کسی بڑی سے بڑی ہستی کا کسی کے خواب میں آنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے کیونکہ کئی غیر مسلموں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی زیارت ہوئی ہے، چنانچہ ایسے خوابوں کی اور خصوصًا اہل بیت کی خواتین سے متعلق خوابوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں ایسی غلط فہمیوں کی بنیاد مدینہ منورہ کے رہائشی شیخ احمد کے پیغامات کو کئی کئی سو لوگوں تک پہنچانے کی گپ سے شروع ہوئی تھی۔ یہ شیخ احمد کوئی دو سوا دو سو سال سے برِ عظیم پاک و ہند کے سادہ لوح مسلمانوں کو یہ پیغام بھیج رہا بلکہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ المختصر اِن چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اِس قسم کے ایس ایم ایس بھیجنے سے پہلے سمجھدار مفتی صاحبان سے دریافت کرلینا چاہیے۔
یہ اور ایسے کئی مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمارے مخصوص سماجی ماحول اور شدت پسند رویوں کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں رواج پاگئی ہیں۔ اسلام ہرگز تنگ نظر مذہب نہیں ہے بلکہ ہمارے سماجی اور ثقافتی رویے تنگ نظر ہیں۔ ہم اپنے سماج اور ثقافت کو اسلام کی وسعتوں سے ہم آہنگ کرنے کی بجائے اسلام کو اِن تنگ نظر رویوں کی عینک پہن کر دیکھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اِس اِفراط تفریط سے پیدا ہونے والی دیرینہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ اِس میں سبھی کا فائدہ ہے۔
واَمّا مَا یَنْفَعُ النّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الارْض۔
ملتان: ہفتہ۔ ۲/ اپریل ۲۰۱۱ء
مطابق ۲۸/ ربیع الاخریٰ ۱۴۳۲ھ
دعوت الی اللہ کا فریضہ اور ہمارے دینی ادارے (۲)
مولانا محمد عیسٰی منصوری
دعوت میں کوتاہی کے ناقابل تلافی نقصانات
قرون اولیٰ کے بعد من حیث الامت دعوت میں کوتاہی سے جو نقصانات ہوئے، ان کی تلافی کبھی نہیں ہوسکتی۔ مثلاً برطانیہ کے بادشاہ جان لاک لینڈ (۱۱۶۷ء --۱۲۱۶ء) جس نے مشہور میگنا کارٹا(منشورآزادی) دیا، جب اس کے پادریوں سے اختلافات بڑھے تو اس نے ۱۲۱۳ء میں مراکش واسپین کے حکمران ناصر لدین اللہ کے پاس سفارت بھیجی جس کے ارکان میں ٹامس ہارڈینٹن، رالف فرنکسوس، ماسٹررابرٹ وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے شاہِ انگلستان کی طر ف سے پیغام دیا کہ عیسائیت پر سے میرا اعتقاد ختم ہو گیا ہے، اگر آپ پادریوں کے مقابلے پر میری فوجی مدد کریں تو میں اپنی پوری رعایا کے ساتھ مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ سفیروں نے مزید کہا کہ ہم انگلستان کے باشندے لاطینی، انگریزی، فرانسیسی زبانوں کے علاوہ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ یورپ میں اسلام پھیلائیں گے، مگر شاہِ مراکش ناصر لدین اللہ نے پیش کش ٹھکرادی۔ ناصرلدین اللہ کو یہ ٹھکرانا بہت مہنگا پڑا۔ نتیجتاًناصرلدین اللہ کی زندگی ہی میں اس کے چھ لاکھ کے لشکر جرّار کو فرانس، انگلینڈ، اسپین کی افواج نے شکست فاش دے کر اسپین کا بڑاحصہ چھین لیا۔ اس طرح ایک عظیم امکان بدترین انجام میں بدل گیا۔ حالیہ دنوں میں مشہور اخبار ٹائمز نے لکھاتھا کہ تیرہویں صدی کے ابتدا میں امکان پیداہوگیا تھا کہ انگلستان خالص مسلم ملک بن جاتا اور برطانیہ میں قرآن کا حکم نافذ ہوتا۔
اسی طرح شہنشاہِ روس ولادیمر اول (۹۵۶ء -۱۰۱۵ء) کا اعتقاد بت پرستی سے اٹھ گیا تو اس نے مسلمان علما کو بلایا اور اسلام کی فطری تعلیمات سے دلچسپی ظاہر کی، لیکن کہا کہ میں شراب کا عادی ہوں، اسے چھوڑنامشکل ہے۔ اس مسئلے میں مجھے رخصت دی جا ئے، باقی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علما رخصت دینے پر راضی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد عیسائی علما نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے رخصت دے دی تو اس نے عیسائیت سے اصولی طور پر مطمئن نہ ہونے کے باوجود مسیحیت قبول کرکے پوری مملکت کو بتوں خالی کروا کر اپنی ساری رعایا کو عیسائی بنادیا۔ ان علما کو اسلام کا مسئلہ معلوم تھا، لیکن وہ شاید دعوت کی اس حکمت سے ناواقف تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف طائف کو زکوٰۃ وجہاد وغیرہ سے وقتی رخصت عطا فرما کر اختیار کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب اسلام قبول کر لیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے۔ اسی طرح ۱۸۹۱ء میں جاپان کے شہنشاہ میجی نے خلافت عثمانیہ کے فرمانروا سلطان عبدالحمید ثانی کو لکھا کہ ہم اتحادی ہیں، ہماری مصلحت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں تاکہ ہمارے درمیان معنوی رشتہ قائم ہوجائے اور فرمائش کی کہ اسلام کو ان کے ملک میں بطور تحفہ بھیجا جائے جیسے کسی دور میں بدھ مذہب بطور تحفہ بھیجا گیا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے ترکی کے شیخ الاسلام اور بڑے علما کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ علما کسی بات پر متفق نہ ہوسکے، باہم مختلف ہو گئے۔ بالآخر سلطان نے شکریہ کا خط لکھا اور کہا کہ ہم بعد میں کبھی (اسلام) کے مبلغین بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ آج جاپان صنعت وٹیکنالوجی کا بے تاج بادشاہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا معطی (اقوام عالم کو امداد دینے والا) اور اقوام متحدہ کا سب سے زیادہ خرچ اٹھا نے والا ملک اور دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ ان ساری ترقیوں کے باوجود واضح مقصد حیات یا قابل برآمد نظریہ نہیں رکھتا۔ جاپانی وزارت خارجہ کے ایک قابل افسر ہڈیاکی کا سے (HIDEAKKASE) نے کہا ہمارے پاس کچھ آدرش (نظریات) ہونے چاہییں جس میں عالم انسانی کے لیے اپیل ہو۔ اگر ہم دعوت کے ان تینوں مواقع میں سے کسی ایک سے بھی فائدہ اٹھالیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ عظیم نقصان دعوت کے مزاج وذہنیت کھودینے کا نتیجہ ہے۔
قرون اولیٰ کے بعد ملت اسلامیہ نے دعوت کو فریضہ سمجھنا چھوڑ دیا
قرون اولیٰ کے بعد عام مسلمان تو درکنار، عام طور پر علماء کرام نے دعوت سے اغماض برتا، ہندوستان کے آٹھ سو سالہ مسلم دور میں علماء کرام یا تو شاہی درباروں سے منسلک ہوکر اپنی دنیوی ضروریات پوری کرنے میں لگے رہے یا اپنے حجروں میں بیٹھ کر درسی کتب پر شروحات وحواشی چڑھاتے رہے یا انہوں نے خود کو مسلمانوں کی ضروریات دین نماز، روزہ ،اور فضائل ومسائل بتانے تک محدود رکھا ،دعوت واشاعت اسلام پر بہت کم توجہ دی گئی،اگر دور غلامی (برٹش دور)میں بھی ہمیں ہوش آجاتا اور ہم آنے والے دور کا اندازہ کرکے اپنی صلاحیت، طاقت اور وسائل برصغیر کے اقوام کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگائے ہوتے تو آج بر صغیر کا نقشہ مختلف ہوتا ، نہ ملت اسلامیہ ہند تین ٹکڑوں میں بٹتی نہ ایک تہائی سے زیادہ حصہ بدترین دشمن برہمن کے یہاں یرغمال بنتا ،تقریباً ہم نے پونے دوسو سال تک ملک کی آزادی کی جو جنگیں لڑیں ان میں کیسی کیسی صلاحیت وصفات والے ہزاروں اکابر علماء ومشائخ نے جام شہادت نوش کیا ،پھانسی پر چڑھے قید وبند اور ہر طرح کے مصائب سے گزرے اس سارے جہاد کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ برہمن جس کی کبھی کوئی حیثیت نہیں تھی آج عالمی صہیونیت وصلیبیت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پوری دنیاسے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے پر کمر بستہ ہے ہماری پوری چودہ سو سالہ تاریخ کا مطالعہ بتاتاہے دعوت کے سوا جہاں کہیں ہمارا جان ومال،وسائل وصلاحیتیں صرف ہوئیں اس کا نتیجہ ہمارے حق میں ہر اعتبار سے تباہ کن ثابت ہوا۔
برصغیر میں مسلم اقتدار کے بعد کی صورت حال
بر صغیر سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہونے کے بعد زوال وتباہی دن بدن بڑھتی گئی حتیٰ کہ اس کا اندیشہ پیدا ہوگیا کہ بر صغیر میں اسپین کی تاریخ نہ دہرادی جائے ان ناز ک حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آپ کے چاروں نامور صاحبزادگان اور سید احمد شہید بریلوی ؒ اور شاہ اسماعیل شہید ؒ کی ہمہ جہت کاوشوں کی بدولت ملت اسلامیہ ہند میں قرآن وسنت کی تعلیم اور دعوت وجہاد کی روح زندہ ہونی شروع ہوئی، پھر حضرت گنگوہی ؒ حضرت نانوتویؒ حضرت شیخ الہندؒ اور ان اکابر سے وابستہ حضرات کی کوششوں نے حالات کو کچھ اور سمبھالا دیا ،جگہ جگہ تعلیم وتعلم اور ذکروفکر کے چراغ روشن ہونے لگے، پھر بیسویں صدی میں شیخ حسن البنّا، ؒ مولانا الیاسؒ ، مولانا ابوالحسن علی ندویؒ اور مولانا مودودیؒ کی دعوتی سرگرمیوں کی بدولت ہماری تعلیم یافتہ نئی نسل، مغربی تہذیب وتمدن مغربی فلسفہ میں پوری طرح ضم ہوکر ختم ہونے سے بچ گئی ،بلاشبہ ان میں سے بعض حضرات نے فکری طور پر ٹھوکریں بھی کھائی ، غرض جب کبھی ملت اسلامیہ پرنازک حالات آئے، تو دعوت ہی سے حالات اسلام کے حق میں پلٹے ایک ایک داعی (شیخ حسن البنّا، مولانا الیاس، مولاناابوالحسن ندوی، ؒ مولانا مودودیؒ )کی بدولت سیکڑوں ہزاروں ادارے وجودمیں آئے ، دوسری طرف تعلیمی ودینی اداروں کے لاکھوں کروڑوں پڑھنے والوں میں سے عموماً اللہ تعالیٰ نے صرف انہی لوگوں سے کام لیا جو کسی داعی یا دین کا درد کڑھن رکھنے والی صاحب نسبت شخصیت سے وابستہ ہوئے۔
مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے
مذہب ہرانسان کی فطری ضرورت ہے جس طرح ایک بچہ ایر پورٹ یا اسٹیشن پر اپنی ماں سے بچھڑ جائے آپ اسے کھلونے چاکلیٹ ٹافی سب کچھ دیدیں لیکن جب تک اسے ماں نہ ملے گی وہ روتا تڑپتا رہے گا، اسی طرح انسان اپنے خالق سے بچھڑ کر کبھی چین وتسکین نہیں پاسکتا،اسے سکون قلب سے جینے کے لیے ضرورت ہے، ایک اطمینان بخش نظریۂ حیات (آئڈیالوجی )کی ضرورت انسانی فطرت ہے، وہ کوئی ایسی آئڈیا لوجی چاہتاہے جس کے ذریعہ کائنات کی اور اپنی زندگی کی توجیہ کر سکے ،مقصد حیات کو پاسکے، خود کو تسکین دے سکے۔
موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ نظریاتی خلا ہے
رشیا کی آئڈیالوجی (کمیونزم )وقتی اور فرضی تسکین تھی جو جھوٹی اور غلط ثابت ہوچکی ہے، اور اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے معاشی بحران میں دوسری آئڈیالوجی یعنی کپیٹل ازم کا نظریہ بھی منہدم ہوچکا،اب دنیا میں زبردست نظریاتی خلا پیداہوگیا۔ ۱۹۹۱ء میں سویت یونین کا انہدام اور ۹؍جنوری ۱۹۹۲ء میں امریکی صدر جورج بش کا ٹوکیو(جاپان)میں ڈنر کے وقت کرسی سے گرپڑنے کے وقت اس دن کے ٹائمس آف انڈیا نے (BUSH COLLAPSES AT TOKYO RECEPTION)کی سرخی لگائی۔ گویا نئی صدی (اکیسویں صدی) شروع ہونے سے پہلے روس کے حقیقی اور امریکہ کے علامتی انہدام نے دنیا میں نظریاتی خلاء کا اعلان کردیا تھا، اس کوصرف اور صرف اسلام ہی پُر کرسکتاہے،کیونکہ علوم کے ارتقا اور جدید سانس نے اسلام کی حقانیت کو پوری طرح ثابت کردیا ہے ، مراکش کے مشہور کرسچن اسکالر ڈاکٹر مورس بوکا ئی نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب ’’بائبل قرآن، اور سائنس‘‘ میں قرآن اور بائبل کے سینکڑوں سائنسی بیانات کوجدیدسائنسی اور علمی تحقیقات کی کسوٹی پر پرکھ کر ثابت کیا ہے کہ جدید سائنس اور علمی تحقیقات کی روسے قرآن کے سینکڑوں سائنسی بیانات میں ایک بات بھی غلط ثابت نہ ہوسکی ،اس کے برخلاف بائبل،ہرسائنسی بیان، جدید علمی تحقیق اور سائنس نے غلط ثابت کرکے رد کر دیا۔ یہ اس مذہب (کرسچن یاعیسائیت)کی بات ہے جو اسلام سے صرف ۵۷۰ سال پہلے کا ہے۔ یہودیت، بدھ ازم اور ہندومت جو عیسائیت سے ہزاروں سال قبل کے ہیں، جدید سائنسی وعلمی دور میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکے۔ یہ مذہب قرآن کے الفاظ میں اساطیرالاولین یعنی پچھلی من گھڑت کہانیوں کا پلندہ ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک باشعور شخص محسوس کرتاہے کہ وہ کوئی کتاب نہیں بلکہ اپنی فطرت پڑھ رہا ہے۔ اسے قرآن فطرت کی آوازیا پکار محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کا انکار نہ صرف اپنی فطرت یعنی خود اپنی نفی کرناہے۔ کون ہے جو خود اپنی نفی کا متحمل ہوسکے! جدید علوم کی روشنی میں آج اسلام ہر شخص کے لیے ایساہی قابل قبول ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی۔
ہرکچے پکے گھر میں اسلام کے داخلے کی پیشین گوئی کاوقت آپہنچاہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے: لا یبقی علی ظہر الارض بیت مدرٍ ولا وبرٍ الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام (مشکوٰۃشریف) روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسانہیں بچے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک جدید ترین الیکٹرونک میڈیا کے باوجودکمیونسٹ بلاک (عظیم سویت یونین) میں اسلام کاپیغام پہونچنا بظاہرناممکن نظر آرہاتھا، مگر سوویت امپائر کے انہدام کے بعد لگتاہے وہاں کی سرزمین اسلام کی کہیں زیادہ پیاسی ہے، چنانچہ برطانیہ کے اخبارڈیلی نائمز نے ۱۲؍مارچ ۱۹۹۰ء کو روس کے بارے میں ایک بالتصویر رپورٹ چھاپی تھی جس کا نہایت بامعنی عنوان رکھا۔ (Karl Marx Makes Room for Mohammad)کارل مارکس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ خالی کرتاہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پیشین گوئی کے پوراہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ آج کا انسان سیاسی مذہب کے بجائے روحا نی مذہب کا متلاشی ہے جس سے سکونِ قلب میسر آئے۔ عصر حاضر کی نئی نسل، خواہ وہ عیسائی، بدھسٹ، ہندوہو، خوب جانتی ہے کہ چرچ اور مندروں کے اسٹیچو (مورتیاں) خدا نہیں ہیں۔ خداوہ ہے جو نہ گرے نہ ٹوٹے۔ دنیا میں بے شمار افراد اذان کے الفاظ کا ترجمہ معلوم کرکے یا نماز پڑھنے کا عملی منظردکھ کر یاقرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ یورپ کے مشہور ادیب واسکالر جارج برنارڈشا نے بہت پہلے پیشین گوئی کردی تھی کہ اسلا م عقل اور فطرت انسانی کے عین مطابق واحدقائم شدہ مذہب ہے اس کی تعلیمات سے کوئی ذہین تعلیم یافتہ شخص انکار نہیں کرسکتا،جدید تعلیم یافتہ ذہن کے لیے اسلام قبول کرنے میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں کہ اگر وہ اسلام کو لیتا ہے تو عقل وسائنس کو چھوڑنا پڑے۔ جارج برنارڈ شا نے تقریباً ایک صدی پہلے کہہ دیاتھا کہ جلد اسلام عظیم سیلاب بن کر تیزی کے ساتھ یورپ کی انسانی آبادیوں میں داخل ہوگا اور مغر ب کے لیے مستقل کا مذہب اسلام ہی ہوگا۔ اسی طرح افریقہ میں عیسائی مشنریوں کی کوششیں پوری طرح پھیل چکی ہیں، لیکن وہاں اسلام تیزی سے اپنی جگہ بنارہا ہے۔ ابھی چندسال پہلے عالمی عیسائی مشنریوں نے ایک چھوٹے سے پس ماندہ افریقی ملک لیبریا (LIBERYA)کی راجدھانی منورویا (MONROVIYA) میں ایک عالمی مشنری نے وہاں کے دس لاکھ مسلمانوں کو کرسچن بنانے کے لیے پانچ ہزار افراد کو اس قدر تیارکیا کہ وہ وہاں کی نصف درجن قبائلی زبانیں بھی روانی سے بولتے تھے۔ انہیں خاموشی سے مسلم قبائل کے درمیان بسادیاگیا۔ وہاں کے علما نے سمجھداری سے کام لیا، انہیں مذاہب کانفرنسوں اور علمی مباحثوں کے ذریعہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پانچ ہزار عیسائیت کے داعی ومبلغین مسلمان ہوکر اسلام کے مبلغ بن گئے۔
جدید علمی و سائنسی دور کا مذہب
قرآن انسانیت کے نام خالق کائنات کا آخری پیغام ہے جس طرح خالق ہر ہر اعتبار سے مخلوق پر حاوی اور غالب ہے اسی طرح اس کا کلام اور پیغام بھی، البتہ ہرہردور کے انسانوں کی ذہنی سطح اور علوم وفنون کے مطابق اس کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے جب فصاحت وبلاغت الفاظ کے دقائق سمجھنے کا دور تھا قرآن کے کلام کی فصاحت وبلاغت اور الفاظ کی تاثیرکا معجزہ ظاہر ہوا،بائبل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جوپیشین گوئیاں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ قوموں کو تسخیر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے (یوحناعارف کا مکاشفہ ۹۰۰/۱۵)یعنی تاثیر والا کلام جس کی تاثیر نے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں جزیرۃ العرب کو تہ وبالا کردیا تھا ،موجودہ دور طبعیات وسائنس کے علوم سے انفس وآفاق کی ہرہرچیزکے متعلق تفصیلی کھوج وتحقیق کا دور ہے تو دنیا حیران ہے کہ جونئی تحقیق اور ریسرچ سامنے آتی ہے وہ قرآن میں موجود پاتی ہے۔
دعوت، آخری دور کا سب سے مؤثر اسلحہ
پتھر کے دور سے لے کر آج الیکٹرونک اسلحہ کے دور تک ہر دور میں اسلحہ کی نوعیت بدلتی رہی۔ آنے والے دور کا اسلحہ دعوت اور میڈیا ہے۔ ماضی قریب میں رشیا کو شکست امریکی اسلحہ نے نہیں بلکہ امریکی میڈیا نے دی تھی۔ معلوم ہوتاہے کہ اسلام کا غلبہ اور فتوحات اسی راہ سے ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک شہر جس کا ایک رخ خشکی کی طرف ہوگا اور دوسرا سمندر کی طرف، دونوں طرف کی شہر پناہ (دیواریں) مسلمان لشکر کے لا الہ الااللہ، اللہ اکبرکے نعرے سے گرجائیں گی۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری دور کا سب سے بڑا اسلحہ دعوت ہوگی اور یہ دعوت مسلمانوں کے عالمی غلبہ وکامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگی۔ بالفاظ دیگر آخری دور میں اسلحہ کے بغیر اسلام کی فکری ونظریاتی اور دعوتی طاقت قوموں کو مسخر کرنے والی ہوگی۔
مغرب میں دعوت کے خلاف عالمی طاقتوں کا خفیہ منصوبہ
موجودہ دور میں قدرت کے مخفی ہاتھ نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مغرب (امریکہ یورپ)میں پہنچادیا ہے۔ شاید ان سے کوئی کام لینا منظورہے۔ ایسے دور میں جب انسانی مسائل کے حل میں سارے نظریات ومذاہب ناکام ہوچکے ہیں اور عصر حاضر کے انسان کو اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے ایک نظریۂ حیات کی اشد ضرورت ہے، شاید فطرت کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ اللہ کا انتظام ہے۔ ہم نے یہاں (مغرب) پہونچ کر سینکڑوں ہزاروں مساجد ومکاتب اور درجنوں دارالعلوم قائم کیے، مگر ایسا چھوٹا سا سینٹر نہیں بناسکے جہاں نو مسلموں کو سال دو سال رکھ کر انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواکر ان کے اپنے معاشرے میں داعی بناکر بھیجیں۔ ہماری اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ تیس چالیس سالوں میں مغرب میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، خواہ وہ اپنی ذاتی جستجوسے مسلمان ہوئے ہوں خواہ یا کسی نے مسلمان کیا، آج وہ سب کے سب شیخ ناظم ترکی کے پاس پہونچ چکے ہیں جس کا کام تصوف کا نام لے کر امت میں تفرقہ پیدا کرنا اور ان نومسلموں کو معطل بناناہے تاکہ وہ دعوت کا کام نہ کرسکیں۔ اس شخص (شیخ ناظم) کے نزدیک امام حرم، عرب علما، علمائے دیوبند ،تبلیغی جماعت، سلفی حضرات سبھی باطل وگمراہ ہیں (غالی قبر پرست بدعتیوں کے سوا)۔ بندہ کی تحقیق کے مطابق یہ شخص عالمی صہیونی طاقتوں کا گماشتہ ہے، اس کا آقا وشیخ مراکش میں صیہونیوں کا ایجنٹ ہے اور اس شخص کو امریکی ایما پر عرب حکمران کروڑوں اربوں روپے دے رہے ہیں۔
دینی جامعات اور عصر ی تقاضے
آج ہماری سب سے بڑی ضرورت اقوام عالم کے لیے داعی تیار کرناہے، اس کام کے لیے نظرباربار ہمارے دینی اداروں (دارالعلوم اور جامعات) کی طرف جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہبر صغیر اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں ان دینی مدارس کا نہایت اہم رول رہا ہے۔ آج ان ممالک میں جودین اور علم دین کے چرچے ہیں، سب انہی کی برکتیں ہیں۔ یہ بلاشبہ دین کے قلعے ہیں،لیکن وقت کے علوم وضروریات کے ساتھ ساتھ ان دینی قلعوں میں بھی آج کی عصری ضرورتوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مضبوط ومستحکم قلعے بھی آثار قدیمہ کے میوزیم بن کر رہ گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دینی مدارس میں تقویٰ وتوکل کی صفات اور عصری تقاضوں کا شعور نہ رہے تو اندیشہ ہے کہ یہ بھی آثار قدیمہ بن کر نہ رہ جائیں۔ گذشتہ دنوں بندہ کا یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک میں جاناہوا جس کی آبادی چند لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ وہاں کی کرسچن مشنری میں دیکھا کہ وہاں بنگالیوں سے اچھی بنگالی، پنجابیوں سے اچھی پنجابی اور ہم سے اچھی اردو عربی بولنے والے موجود ہیں جبکہ عیسائیت ایک غیر دعوتی مذہب ہے۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ مشہور ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑو ں کے لیے بھیجا گیا ہوں، جبکہ اسلام ایک دعوتی دین ہے۔ گذشتہ ڈیڑھ صدی میں ہمارے جامعات نے کتنے ایسے داعی تیار کیے جو اسپینش، جرمنی، فرانسیسی یا رشین زبانوں میں دعوت دے سکیں۔ گذشتہ ڈیڑھ صدی میں برصغیر میں دین کا بنیادی کام انہی دینی مدارس نے انجام دیا۔ ان اداروں سے کماحقہ فائدہ اسی وقت تک ہواجب تک وہ اصل بنیادتقویٰ وتوکل پر قائم رہے۔ یا درکھئے! ہماری بنیاد تقویٰ وتوکل، اور کفر کی بنیاد ملک ومال ہے اور بنیاد مثل زمین کے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین پر اپنی عمارت تعمیر کرلے تو صاحب زمین جب چاہے کہہ سکتا ہے اپنی عمارت اٹھاکرلے جاؤ، میری زمین خالی کرو۔ تقویٰ و توکل کے بجائے مال کی بنیاد پر بننے والے عظیم الشان جامعات گویا دوسروں کی زمین پر کھڑے ہیں۔ ایسے ادارے باطل کی ایک آندھی کامقابلہ نہیں کرسکیں گے، جیسے وسط ایشیا کے ممالک میں ہوا۔ سمرقند،بخارا،تاشقندوغیرہ میں سینکڑوں عظیم الشان دینی جامعات تھے۔ کمیونزم کی ایک آندھی چلی اور سب جامعات زمیں بوس ہوگئے۔ روحانی صفات، تقویٰ وتوکل سے عاری فارغ ہونے والے مولوی صاحبان کی فوج ظفر موج باطل کے ایک جھونکے کی تاب نہیں لاسکے گی۔ وسط ایشیا میں علما اور عوام کا جوڑختم ہوگیا تو وہ عوام جو علما کے ہاتھ چومتے تھے، خود انہوں نے ان علما کی گردنیں کاٹیں۔
افراد سازی میں ہمارے دینی جامعات و مدارس کی ناکامی
تقریباً ایک صدی پہلے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب ؒ نے لکھا تھا کہ ہمارے مدارس اور خانقاہ بانجھ ہوتے جارہے ہیں۔ غور کریں توہمارے زکوٰۃ وصدقات کا بڑاحصہ دینی مدارس اور دارالعلومو ں پر خرچ ہورہاہے، مگر ان سے زیادہ تر معمولی صلاحیت کے لوگ مل رہے ہیں، رسمی امام وخطیب یامکتبی مولوی۔ ان بیچاروں کی اکثریت عربی تو درکنار، صحیح اردو لکھنے پڑھنے سے بھی عاری ہے۔ پھر یہ حضرات جو لکھتے بولتے ہیں، درسی زبان میں ہوتاہے جو عام لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزرجاتی ہے۔ برطانیہ میں پہلے ہم سوچتے تھے یہاں کوئی بڑا دارالعلوم ہوناچاہیے تاکہ یہاں کے ضروریات وتقاضوں کو پورا کرنے کے لیے افراد کار میسر آسکیں۔ اب درجنوں دارالعلوم قائم ہوگئے، لیکن ہماری ضرورتیں جوں کی توں ہیں۔ اگر ان جامعات کا حاصل مکتب میں پڑھنے والے مولوی صاحبان اور مساجدکے اما م ہی ہے تو مکتبی مولوی اور مسجد میں نماز پڑھانے والے امام ان دارالعلوموں سے پہلے بھی میسرتھے۔
دعوت کا جذبہ اور فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت
اگر کوئی شخص طالب علم بن کر ہمارے پاس آتاہے توضروری ہے کہ اس کی نسبت اور ارادہ دین کے کام کرنے کا ہو کہ مجھے اب زندگی میں صرف دین کا کا م کرناہے، اور اہل مدارس کو بھی چاہیے کہ جن طلبہ کے بارے میں اندازہ ہو کہ ان میں نہ دین پھیلانے کا جذبہ ہے نہ دین پر چلنے کا شوق تو انہیں ضروریات دین کا علم دے کر دوسال میں فارغ کریں۔ ملت کا پیسہ ان پر ضائع نہ کریں۔ موٹی سی بات ہے، اگر کسی شخص کو محض اپنی ذاتی قابلیت پیداکرنے یااپنے معاش کے لیے علم وہنر سیکھنا ہے تو اسے اپنے ذاتی اخراجات سے سیکھنا چاہیے، جیسے دنیا میں ہر شخص کار چلانا، کمپیوٹر کا استعمال، ہندی انگریزی زبان اپنے اخراجات سے سیکھتاہے۔ ملت کی زکوٰۃ وصدقات کی امانت ایسوں پر پرکیوں ضائع کی جائے؟ ہمارے دینی مدارس کے اخراجات کا خاصا بڑاحصہ ایسے لوگوں پر ضائع ہورہاہے جودین پھیلانے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ دعوتی اسپرٹ کے بغیر طالب علم کو علم دینا ایساہی ہے جیسے کوئی کاغذوں میں علم جمع کردے یا آڈیو، ویڈیو کیسٹ میں بھر دے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام دعوت کے ذریعہ انسانوں کے دلوں کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف اور خواہشات سے رضاے الٰہی کی طرف موڑدیتے تھے، پھر انسان کی ساری زندگی آخرت بنانے کی فکر اور رضاے الٰہی کی طلب میں گزرتی تھی۔ ہم مدارس کے ذریعہ کسی درجہ میں علوم تو دے رہے ہیں، مگر ان کے دلوں میں فکر آخرت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جب دلوں میں دنیا بسی ہو تو انسان کی ساری علمی صلاحیتیں بھی اپنی دنیا بنانے پر صرف ہوتی ہیں۔ ادھر چندسالوں میں ہمارے دینی وتعلیمی جامعات میں تخصص کے شعبہ جات قائم کرنے کا ذوق اور رجحان بڑھ رہاہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ زمانہ کسی فن میں تخصص ہی کا ہے۔ ہرعلم وفن ایک وسیع سمندر ہے۔ انسان کسی ایک شعبۂ علم میں بھی بصیرت ورسوخ پیداکرلے تو بڑی بات ہے، مگر یہاں بھی اصل خرابی یہی ہے کہ صلاحیت پیداکرنے کے ساتھ دلوں کا رخ آخرت کی طرف کرنے پر توجہ نہیں۔ اگرہم بنظر غائر دیکھیں کہ گذشتہ پچیس تیس برسوں میں دیوبند سے کیرالہ تک جن طلبہ نے دینی علوم وفنون میں تخصص کیا، مثلاً قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، ادب، معاشیات، انگریزی زبان، عربی زبان، کمپیوٹر کا استعمال وغیرہ وغیرہ، ان میں کتنے فیصد طلبہ انسانوں کوخدا کی طرف بلانے یا ان تک دین پہنچانے میں مصروف ہیں؟ آج ان کی بھاری اکثریت ریڈیو اسٹیشنوں، اخبارات، چینلوں میں کام کرنے، ترجمہ کرنے، کمپیوزنگ کرنے یا پروگرام ترتیب دینے میں مشغول ہے یا کسی عرب سفارت خانہ میں ملازمت یا ملٹی نیشنل کمپنیوں میں خدمات انجام دیتی نظر آتی ہے۔ کیاملت کے لاکھوں کروڑوں روپے اس لیے صرف کیے گئے تھے کہ چندعلما کے معاشی حالات اور معاشی زندگی معیاری ہو جائے؟
قرآ ن وسیرت کے بجائے فقہ میں زیادہ اشتغال کے نقصانات
صدیوں سے بر صغیر کے علماء کرام کا زیادہ تر اشتغال فقہ میں رہا کیوں کہ مسلم دور حکومت میں قاضی محتسب اوقاف ووصایا کے متولی ونگراں عہدے، مناصب اور روزی فقہ سے وابستہ تھیں۔ اس کے برخلاف قرآن وسیرت نبوی پر توجہ بہت کم رہی۔ برصغیر کے آٹھ سو سالہ مسلم حکمرانی کے دور میں شاید سیرت پر کوئی جامع کتاب نہیں لکھی گئی، نہ نصاب تعلیم میں سیرت اور قرآن پر کوئی توجہ تھی۔ (الحمدللہ بیسویں صدی میں علماء ہند (جیسے شبلی نعمانیؒ ، سید سلمان ندوی، قاضی سلمان منصور پوری، مولانا مناظرا حسن گیلانی وغیرہ) نے سیرت پر اعلیٰ درجے کا علمی وتحقیقی کا م کرکے تلافی کردی۔ اس (فقہ) کی جھلک برصغیر کے نصاب و نظام تعلیم میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ نودس سالہ نصاب تعلیم میں اصل توجہ فقہ پرہی رہتی ہے، آخری سالوں میں قرآن اور احادیث کو اپنے اپنے فقہی مسلک کے سانچے میں ڈھال کر پڑھا دیا جاتاہے، جبکہ اصل کسوٹی قرآن وسنت ہونی چاہیے نہ کہ متأخرین کے فقہی اجتہادات وفتاویٰ۔ اس ترتیب وذوق کا بہت بڑا نقصان یہ ہواکہ ہمارے یہاں ہر دور میں فقہ القرآن اور فقہ الحدیث کا ملکہ رکھنے والے افراد کمیاب بلکہ نایاب رہے۔
فقہ دور عباسی میں مرتب ہوئی جو ہماری قوت وطاقت اور دنیا بھر پر حکمرانی کا دورہے۔ دور عباسی کے بعد بھی ہم صدیوں تک دنیا بھر میں غالب وحکمران ملت اور سُپر پاورامت کے طور پر تھے، اس لیے ہمارے فقہی ذخیرہ میں قوت وطاقت اور حکمرانی کے دور کے لیے لائحۂ عمل پوری تفصیل کے ساتھ ملے گا، لیکن بے بسی اور کمزوری کے دور کا جب ایک تہائی مسلمان اقلیت میں دوسروں کے رحم کرم پر ہو ں اور باقی مسلم حکومتیں بھی دنیا کی باطل ودجالی طاقتوں کے سامنے مجبور محض ہوں، ایسے دور کے لیے لائحۂ عمل اور مکمل رہنمائی جسے ہم فقہ الاقلیات یا بے بسی کے دور کا لائحۂ عمل کہہ سکتے ہیں، ہمارے فقہی ذخیرہ میں بہت کم ملے گا، کیوں کہ جس دور میں فقہ مرتب ہو ئی، اس کے بعد صدیوں تک فقہائے کرام اس کا تصور بھی نہیں کرسکتے تھے کہ کبھی دنیا میں ایسادور بھی آسکتاہے کہ دنیا بھر کے مسلمان کفر کے سامنے ایسے بے بس ولاچار مجبور ومظلوم بن کر زندگی بسر کررہے ہوں۔ اس کمزوری اور ضعف کے دور کے لیے زندگی کے ہر شعبہ کامکمل اور تفصیلی لائحہ عمل قرآن اور سیرت میں ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پوری زندگی اور نزول قرآن کا سارا دور مسلمانوں کی بے بسی اور کمزوری کا دور تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر ایک نظر ڈالنے سے آٹھ ہجری تک کی صورت حال کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس صلح نامہ میں ہمارے عصرحاضر کے مسائل ومشکلات میں بہت کچھ رہنمائی اور بصیرت ہے۔ اگرچہ فتح مکہ پورے جزیرۃ العرب کی فتح کے ہم معنی تھی، مگر اطراف کی قوتوں، پرشین امپائر اوررومن امپائر کے عزائم کو سامنے رکھا جائے اور غزوہ تبوک اور جیش اسامہ کا پس منظر سامنے ہو تو سمجھاجا سکتاہے کہ بالکل آخری دورتک دشمنان اسلام کی طاقت وقوت کا دور ہے۔ مسلمانوں کو حقیقی اور صحیح معنی میں قوت دور فاروقی میں حاصل ہوئی۔ اس لیے پوراقرآن اور پوری سیرت گویا ہمارے آج کے دور کے لیے تفصیلی اور مکمل رہنمائی اور ہرہرشعبۂ زندگی کے لیے لائحۂ عمل ہے ،مگر ہم ہیں کہ فقہ میں اشتغال کے ذریعہ اپنے غلبہ وقوت دنیابھر پر حکمرانی کا دور سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے عصری مسائل میں اپنے لیے نہ کوئی راہِ عمل متعین کر پارہے ہیں نہ اپنے مسائل کا حل نکال پا رہے ہیں۔
آج کے دور میں ہمیں فقہ کے متعدد ابواب جیسے کتا ب الرقاق، کتاب الغنیمۃ بے جوڑ اور ناممکن نظر آتے ہیں۔ بندہ کے نزدیک اپنے غلبہ کے دورمیں مرتب ہونے والی فقہ پر ساری توجہ دینے کی وجہ سے نہ ہم آج کا دور سمجھ پارہے ہیں نہ موجودہ حالات میں اسلام کے غلبہ کی راہیں تلاش کر پا رہے ہیں۔ لگتاہے گویا ہم پر سارے دروازے بندہیں، مجبوری اور معذوری میں زندگی بسر کرناہی ہمارا مقدر ہے۔ یہ ساری مصیبت فقہ القرآن اور فقہ السیرت سے ناواقفیت اور غفلت کی وجہ سے ہے، ورنہ سیرت پاک اور قرآن حکیم آج کے دور کی رہنمائی سے بھراپڑاہے۔
برصغیرکے دینی مدارس کا اصل امتیاز
برصغیر میں دیوبند جیسے دینی مدارس کی اصل کامیابی وطاقت جس کا لوگوں کے دلوں پر سکہ جماہواہے، وہ تصنیف وتالیف، ریسرچ وتحقیق اور دوسرے علمی کارناموں کانہیں ہے، ان میں دوسرے ادارے مثلاً جامعہ ازہر بہت آگے ہے جہاں ہر طالب علم کو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنا لازم ہے، بلکہ اعظم گڑھ کا معمولی سا چند کمروں پر مشتمل ادارہ دارالمصنفین بھی شاید تصنیفی وتحقیقی کا م میں آگے ہے۔ ہمارے دینی مدارس کا اصل امتیاز وخصوصیت تقویٰ وتوکل، تعلق مع اللہ، اتباع سنت، زہدو قناعت والی زندگی، ملت کا درد وغم، دین کی خاطر مر مٹنے اور جاں فروشی کے جذبات ہیں۔ اگر یہ صفات نہ رہے تو دیوبند جیسے مدارس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ موجودہ دور کا سب سے تشویشناک پہلو یہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ؒ کے بعد کئی پشتوں (تقریباً ڈیڑھ سو سالہ) دینی، تعلیمی واصلاحی جدوجہد کے برگ و بار آنے کا وقت آیا تو تقویٰ وتوکل کی جگہ عالی شان عمارتوں اور ما ل کی ریس نے دینی اداروں کو کھوکھلا اور بے روح بنادیا۔ خاص طور سے گذشتہ تیس چالیس سال سے ساری توجہ ظاہری شان وشوکت والی عمارتوں نے کھینچ لی، علم اور مجاہدے کا دور ختم ہوگیا، ایمانی صفات میں ضعف آگیااور افراد سازی سے توجہ ہٹ گئی۔ ہماری صفوں میں بہت سی کالی بھیڑیں داخل ہوگئیں، دینی مدارس کی عمارات جتنی بلندوبالا اور خوبصورت بنتی گئیں، ظاہری سجاوٹ کے ساتھ دلوں کی باطنی دنیا اجڑ تی گئی۔ تعلق مع اللہ، تقویٰ وتوکل، زہدوقناعت، سادگی اور جفاکشی کم ہوتی گئی۔ بلاشبہ بہت سے دینی مدارس میں کسی درجہ میں یہ صفات باقی ہیں اور کسی نہ کسی درجہ میں افراد کا ر بھی وہاں ہی تیار ہو رہے ہیں، اکیسویں صدی داخل ہونے تک ہمارے تعلیمی ادارے ظاہراً تو بہت بارونق اور عالی شان ہوگئے، مگر علمی وروحانی اخلاقی عملی طورپر بھیانک تباہی آگئی۔ آخرت کی طلب، دنیا سے بے رغبتی، دین پر مر مٹنے کا جذبہ، عوام تک دین پہنچانے کی تڑپ وکڑھن اور نبیوں کی طرح بے طلب لوگوں میں دین پہنچانے کے لیے مارے مارے پھر نا ماضی کی داستان بن گیا۔ اب دینی ادارے دکان اور فیکٹریوں کی طرح چلائے جانے لگے۔ یہ مدارس ذاتی، خاندانی اور موروثی جائیداد بن گئے جس کی وجہ سے موروثیت کی تمام خرابیاں اور فساد درآیا۔
آج کل دین کے نام پر ہم مولویوں کی ساری جدوجہد کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں پیسے دو، ہم اپنا ایک الگ ادارہ قائم کریں گے۔ ہم میں ہر شخص کے پاس کروڑوں اربوں کے منصوبے اقوام عالم تک ایمان واسلام پہنچانے یا ملت اسلامیہ کی تربیت وافراد سازی کے نہیں، محض عالی شان عمارات بنانے کے ہیں۔ دین کے نام پر ہر وقت مانگنے والا پیشہ ور طبقہ پیداہو گیا ہے۔ بقول مولانا زاہدالرشدی کے آج ہمارے بہت سے مولوی صاحبان کا تعارف وشناخت یہ ہے: ہر وقت مانگنا، ہر ایک سے مانگنا اور ہر چیز مانگنا۔ کسی معاشرہ میں مانگنے والے کا جو مقام وحیثیت ہوتی ہے، وہی ہماری بنتی جا رہی ہے۔ اگر اب بھی ہم نے سنجیدگی سے اس مسئلہ کو نہ لیا تو عالم بننا اعزاز کے بجائے ذلت کا لیبل بن جائے گا اور شاید سمر قند وبخارا کی تاریخ یہاں بھی دہرا دی جائے۔
دینی مدارس کی موجودہ صورت حال کا ایک جائزہ
اگرچہ ہر مدرسہ کے ذمہ دار زبان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سے فارغ ہونے والے دنیا میں دین پھیلائیں گے، سوال یہ ہے کیسے پھیلائیں گے جبکہ آپ نے نہ دعوت کی تربیت، دی نہ داعی کامزاج بنایا، نہ آخرت کی فکر پیداکی، نہ روحانی وباطنی اوصاف سے آراستہ کیا بلکہ وہ بھی اوروں کے دیکھا دیکھی دین کے نام پر اپنی ذاتی جائیداد یں بنائیں گے۔ آج صورت حال یہ ہوگئی ہے کہ ہر مولوی جوچرب زبانی سے اہل مال کی جیب سے مال نکلوانے کا فن جانتاہے، وہ رئیس الجامعہ یا حضرت مہتمم صاحب سے کم پر راضی نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ مہتمم بنتے ہی میری اولاد، دامادوں اور دیگر رشتہ داروں کی روزی کا مسئلہ مستقل حل ہوجائے گا۔ حضرت مہتمم صاحب سے کون پوچھ سکتاہے کہ آپ نے خود کی اور اولاد کی تنخواہ کس معیار پر مقرر کی، اس لیے وہ کسی قدیم بنے بنائے ادارے میں خدمات انجام دینے کے بجائے اپنا جامعہ ضروری سمجھتاہے۔ اگر مہتمم کا کوئی علمی، اخلاقی ورحانی معیار مقرر کرکے امتحان لیاجائے تو شاید نوے فیصد مہتمم صاحبان فیل ہو جائیں گے۔ بندہ نے یہاں انگلینڈ میں اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا کہ اپنا جامعہ قائم کرنے کی خاطر مولوی صاحبان ہر قسم کی عصبیت جاہلیت، علاقائی، ضلعی، گروہی، لسانی، برادری وقومی حتیٰ کہ ایک ہی ضلع کے لوگوں میں شہر سے آنے والے اور دیہات سے آنے والے اور براہ راست انڈیا سے آنے والے اور افریقی ملکوں میں جاکر آنے والوں میں عصبیت بھڑکائی تاکہ میرے ضلع، گاؤں برادری کا پیسہ باہر نہ جائے۔ کیا ایسے دارالعلوموں سے للہٰیت اور مجاہدے کے ساتھ دین کا کام کرنے والا طبقہ پیدا ہوگا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل بالکل ترک کردیا ہے۔ ہم میں کوئی کسی منکرپر نکیر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میری مقبولیت اور تعلقات میں فرق نہ پڑے، مجھے سبھی اچھا سمجھتے رہیں۔ ہمارے بعض بزرگ جو اہل مدارس کے نزدیک نہایت محترم سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی نجی مجالس میں ان خرابیوں کا تذکرہ کرلیتے ہیں مگر براہ راست ان ذمہ داروں کو ٹوکنے کے لیے تیار نہیں۔ جامعہ کے معنی یونیورسٹی کے ہیں جو ضلع میں ایک آدھ ہی ہوتی ہے، مگر یہاں دومیل کے فاصلے پر اور ایک ہی بستی میں متعدد جامعات بن رہے ہیں۔ جامعہ کہاں کس جگہ کس سائز کا بنے، آج یہ سب ایک فرد کی مرضی پر موقوف ہے جسے حضرت مہتمم صاحب بننا ہے۔
ابھی اکتوبر۲۰۱۱ء کے اخیر میں استنبول (ترکی) میں حجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ پر منعقد ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس میں بندہ سے ایک رئیس الجامعہ صاحب فرمانے لگے، مولانا! آپ ہم سے بہت خفالگتے ہیں اور سخت الفاظ میں ٹوکتے اور لکھتے ہیں، مثبت کام کیجیے۔ بندہ نے عرض کیا، آپ تمام حضرات تو ماشاء اللہ مثبت کا م کرہی رہے ہیں۔ لاکھوں مولوی مثبت کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا اتنا سارا مثبت کا م کافی نہیں ہے؟آج ہم نے مداہنت کو مثبت کام سمجھ لیا ہے۔ یہ دکانوں کے انداز پر قائم ہونے والے شخصی جامعات نااہل مولویوں کا ڈھیر لگاتے جارہے ہیں جس کی وجہ سے علم اور علما دونوں کا وقار اور عظمت مٹی میں مل رہاہے۔ جیسے کسی شہر میں پچاس ڈاکٹروں کی ضرورت ہو، آپ وہاں پانچ سو ڈاکٹر پیدا کر دیں تو ڈاکٹروں کی نہ صرف قدروقیمت ختم ہوجائے گی بلکہ ڈاکٹر صاحبان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اپنے پورے طبقہ کی ذلت کا سبب بنیں گے۔ یہی ہم مولویوں کی صورتحال ہے۔ یادرکھیے! تعلیم وتعلم یا دین سکھانے کے دو مرتبے ہیں۔ ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین ہے ہر مسلمان کو اس کی ضروریات کا علم دینا اور فرض کفایہ ہے کچھ افراد کو پورے دین کا تفصیلی علم دلائل کے ساتھ دینا۔ آج ہماری ساری توجہ فرض عین کے بجائے فرض کفایہ پر ہے، کیوں کہ فرض عین میں نبیوں کی طرح جان کھپانی پڑتی ہے اور لوگوں میں مارے مارے پھرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس فرض کفایہ میں لگنے سے ہم حضرت مہتمم صاحب اور حضرت رئیس الجامعہ بن کر اپنے حلقوں اور بستیوں کی اہم شخصیت بن سکتے ہیں جسے بندہ اسلامی وڈیرے وجاگیر دار کہتاہے۔
دعوت کی مثال بادل کی سی ہے کہ بادل ہر جگہ خود جاکر بے طلب لوگوں پر برس کربنجر زمینوں کو سیراب وشاداب بنادیتاہے اور دینی اداروں کی مثال کنویں کی سی ہے جسے طلب وضرورت ہو، ہمارے پاس آئے۔ حضرات انبیا علیہم السلام بادل بن کررہتے تھے، نہ کہ کنواں بن کر۔ حضرت مولانا سعیداحمد خان مکی فرمایا کرتے تھے: کُن عالماً ولا تکن مولویاً۔ اگر بھارت کے پندرہ کروڑ مسلمانوں کو آپ مولوی قاری حافظ مفتی بنادیں تو کیا آپ کے سارے مسائل حل ہوجائیں گے؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، سارے تعلیمی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، تہذیبی و فکری مسائل اپنی جگہ پر رہیں گے۔ بلاشبہ دین کے لیے دارالعلوم اور جامعات ضروری ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ سارے مولوی صاحبان ملت کے تمام اجتماعی مسائل سے آنکھیں بندکرکے ایک ہی کام کرتے رہیں۔
علماء کرام کی عوام سے لاتعلقی خطرے کی گھنٹی
آج سب سے تشویشناک اور فکر انگیز مسئلہ یہ ہے کہ اگر چہ دینی اداروں کی بہتات ہے، مگر علما اور عوام کاجوڑ وتعلق ختم ہوتا جارہا ہے۔ آج برصغیر کے تینوں ملکوں میں جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر علماء کرام اور طلباء مدارس ہوتے ہیں۔ عام مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ نظرآتے ہیں۔ ہمارے کاشتکار، ہمارے تاجر، ہمارا ملازمت پیشہ طبقہ، ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ اور ملت اسلامیہ کے دیگر طبقات کے لوگوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ کیا دین واسلام ان کا مسئلہ نہیں ہے یا انھیں دینی رہنمائی کی ضرورت نہیں؟ یہ صورتحال خطرے کی گھنٹی ہے، باطل طاقتیں ایسے ہی مواقع سے فائدہ اٹھاکر مسلم عوام کوورغلا کر علما کے خلاف استعمال کرتی رہی ہیں۔ اگر علماء کرام کا اپنے عوام سے مضبوط تعلق قائم رہے تو باطل کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوسکتی۔ ماضی میں سمر قند، تاشقند اور بخارا کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علماء کرام اپنے عوام سے بے تعلق اور بے نیاز ہوگئے تھے، اس سے فائدہ اٹھاکر کمیونسٹوں نے مسلم عوام کو بھڑکاکر انہیں کے ہاتھوں علماء کرام، مدارس ودینی شعار کا خاتمہ کروایا۔ آج بھی باطل طاقتوں کی پوری کوشش ہے کہ مسلم عوام کو علماء کرام سے دور کیاجائے۔
ہمارے اکابرین اپنے گاؤں ضلع علاقہ میں عوام سے گہراتعلق رکھتے تھے، جیسے مظاہرعلوم وقف کے حضرت مفتی مظفر حسین ؒ صبح دوتین گھنٹے حدیث کا درس دیتے اور ظہرکے بعد اکثر اطراف کے کسی گاؤں یادیہات میں جاکر لوگوں سے ملتے، دین کی باتیں بتاتے، موسم خواہ کتناہی سخت ہو، سخت گرمی ہویا سردی یا بارش ہو۔ آخری عمرمیں لوگ عرض کرتے کہ حضرت! آپ کی صحت کاتقاضا ہے کہ آرام کیجیے، ان گاؤں والوں کویہیں بلوالیتے ہیں توفرماتے، وہاں سے دوچار آدمی آئیں گے، لیکن جب میں وہاں جاؤں گا تو پورا گاؤں مجھ سے ملے گا، دین کی باتیں مجھ سے سنے گا۔ اسی طرح حضرت مولانا صدیق احمد باندویؒ اور دیگر اکابرین عام مسلمانوں سے وابستہ رہتے تھے، جبکہ آج ہم عوام سے کٹتے جا رہے ہیں۔ اس مسئلہ پر ہمیں سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
دینی حلقوں میں عدم برداشت ۔ مضمرات و نتائج
محمد اورنگ زیب اعوان
دینی حلقوں میں عدم برداشت کی موجودہ کیفیت نئی نسل کے لیے انتہائی اضطراب کا باعث بن رہی ہے۔بات بات پہ فتوے، تنقیدات ، الزامات اور تہمتوں کی اس روش نے ذہنی ارتداد کی کیفیت کو جنم دیا ہے۔ ہمارے سنجیدہ اہل علم کواس معاملہ میں باہم سوچ وبچار کے بعد ایسی مشترکہ پالیسی طے کرنی چاہیے جس کے باعث ایسے معاملات کی راہ روکی جاسکے ۔کوئی رائے دینے،کچھ کہنے اور لکھنے سے پہلے اس کے تمام مثبت ومنفی پہلوؤں پر نظر رکھنی چاہیے۔فوائد اور نقصانات اگر مدنظر ہوں تو امید ہے کہ اختلافات کی صورتیں کم ہی پیدا ہوں گی ۔محض شخصی اور ذاتی مقاصد ومفادات کے حصول کی خاطر کسی رائے کے اظہار میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑناچاہیے۔ دوسروں کو جبراً قائل کرنے کے بجائے صبراً مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ۔ہمارے اکابر اپنے اصاغر کی اصلاح اس انداز میں کریں کہ وہ محسوس کریں کہ جیسے والد اپنے بیٹے کی اصلاح کرتا ہے ایسے ہی یہ بزرگ ہماری اصلاح فرمارہے ہیں ۔
تنقید اور جارحانہ اندازِ اصلاح ، اصلاح کی بجائے فساد کا سبب بنتا ہے ۔ہم محض جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے ؟اور جب پانی سر سے گذ رجاتا ہے تو پھرسوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ۔سانپ گذر جائے تولکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔اسی طرح لکھتے ہوئے بھی ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر لکھنا چاہیے، تقریرسے زیادہ تحریر اثرانداز ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احسا س پید ا ہوجائے کہ ہم نے بولے جانے والے ایک ایک کلمہ اور لکھے جانے والے ایک ایک لفظ کا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے تو ہماری زبان اور قلم بہت ہی محتاط ہو جائیں۔
ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہماری منفی تحریروں کے نقصانات کتنے زہریلے مرتب ہوتے ہیں ۔ہمارا مخالف اور مخاطب تو جواثر لے وہ تو ہے ہی مگر اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ دین دشمن افراد اور جماعتوں کے پاس ہمارا تمام ریکارڈمحفوظ ہورہاہے اور وقت آنے پر وہ ہماری نسلوں کو ہم ہی سے نہیں بلکہ دین اسلام سے بدظن اوربرگشتہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جیساکہ ’’تاریخ احمدیت ‘‘لکھ کر قادیانیوں نے کیا ہے اور منکرینِ حدیث اپنی کتابوں میں کررہے ہیں۔صرف مذہب کا سرطان۔(مرتب:کوثر جمال)،تاریک اجالے،حقیقی علماء اور جعلی علماء ۔احتساب یا انقلاب ، حقیقی عبادت جعلی عبادت ۔(مرتب:مشتاق احمد)اور پسِ نوشت (ڈاکٹر پرویز پروازی) کا دیکھناہی اس حوالہ سے ہماری آنکھیں کھولنے اور غفلت کی چادر اتارنے کے لیے کافی ہو گا۔
پورے ملک میں چند گنی چنی شخصیات کے استثناء کے بعد ہمارے ہاں کون ہے جواس نہج پر سوچ کر بولے اور لکھے ؟ ہم پہلے جذبات کی رَو میں بہہ کر ایسی باتیں اور فتوے تحریر کر جاتے ہیں اور بعد میں ان کی وضاحتیں پیش پیش کرتے کرتے عمر بیت جاتی ہے ۔آغاز ایک تحریر سے ہوتا ہے اور اختتام ایک کتاب پر جاکے ہوتا ہے ۔کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ فتویٰ پہلے دے دیا جاتا ہے اور فریق ثانی سے متعلق دلائل وشوائد بعد میں اکٹھے کئے جاتے ہیں۔
کراچی کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت نے ایک تنظیم کے خلاف فتویٰ تحریر فرمانے کے بعدمردان کے ایک عقیدت مندکو تحریر کیا کہ فتویٰ تومیں نے دے دیا ہے مگر ان سے متعلق بنیادی معلومات بھی مجھے نہیں ہیں۔آپ براہ مہربانی ان سے متعلق بنیادی معلومات مجھے فراہم کریں۔۔۔ ہمارے ایک انتہائی قابل احترام ’’کالم نگار‘‘دوست نے ایک دفعہ حضرت مولانا زاہد الراشدی مدظلہ العالی سے استفسار کیا تھا کہ حضرت ! ہم جب لکھتے ہیں تو بار بار کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، تین چار دفعہ کی ریاضت کے بعد کہیں جاکے ’’کالم ‘‘ مکمل ہوتا ہے جب کہ آپ کو بارہا دیکھا کہ آپ لکھنے بیٹھتے ہیں اورایک ہی نشست میں اپنا ’’کالم‘‘ مکمل کرلیتے ہیں اوراس میں کہیں کانٹ چھانٹ بھی نہیں کرتے ، تو اس کی وجہ کیا ہے ؟مولانا زاہد الراشدی صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا بھائی! آپ لکھنے کے بعد سوچتے ہیں اور میں لکھنے سے پہلے سوچتا ہوں ۔دوسری طرف وہ ہیں کہ ’’کالم ‘‘ہی نہیں ’’فتویٰ‘‘ ارشاد فرمانے کے بعد سوچتے ہیں بلکہ بعض تو فتویٰ جاری کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے ۔۔۔! انا للّٰہ و انا الیہ راجعون.
پھر نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ فریقین میں تبادلہ دلائل کا نہیں الزامات واعتراضات کا ہوتا ہے ۔ اوریہ الزامات و اعتراضات بھی علمی نہیں ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ہم اُسے تحریر کاحسن سمجھتے رہتے ہیں کہ جتنا کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے اتناہی تحریر میں زور پڑے گااورا دب کی چاشنی بڑھے گی ہمیں یہ احساس سرے سے نہیں ہوتا کہ ایسا کرکے ہم کسے خوش کررہے ہیں اورہماری ان تحریروں سے کل فائدہ کون اٹھائے گا؟
ابھی تک ہماری ماضی کی تحریروں سے ہی گلوخلاصی نہیں ہوئی، پہلے ہی اعتراضات وجوابات کا سلسلہ تھمنے نہیں پایا کہ اب مزید نئے نئے مسائل نے جنم لیناشروع کردیا ہے اوراس کی سب سے بڑی وجہ فریقین میں عدم برداشت اور عدم حوصلہ ہے۔ ہر فرد ، ہرادارہ ، ہرجماعت یہی سمجھتی ہے کہ جوہماری رائے ہے وہی ’’اقرب الی الحق‘‘ ہے اور اب تو بات اقرب سے ہٹ کر ’’عین الحق‘‘ تک پہنچ گئی ہے کہ جو میں کہتاہوں ، جو میرا نظریہ ہے ، جو میری سوچ ہے ، جو میں لکھتا ہوں ، وہی حق ہے، صحیح یہ ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل، لغو اور غلط ہے۔ انا ولاغیری ہی آج ہمار انعرہ ہے۔ اسی سوچ اور نظریے نے آج ہمیں جس مقام پر لاکھڑا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایسے معاملات میں شیطان اوراس کے چیلے ہمارے سامنے ایسے ایسے دلائل لا کر رکھ دیتے ہیں کہ پھرہم رکنے اور ٹھہرنے کا نام تک نہیں لیتے اورایک دوسرے پر ایسے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ ۔
خدا را ہمارے اکابرومعاصر اپنے اس عمل پر نظر ثانی فرمائیں اور امت کے اس بکھرے شیرازے کو مزید انتشار وافتراق کی دلدل میں نہ دھکیلیں۔اکابرکے ساتھ ساتھ اصاغر کوبھی اس کا احسا س کرنا چاہیے کہ:
موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں
الخیر مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم اور البرکۃ مع اکابرکم اہل العلم کا سنہری اصول ہمارے سامنے رہناچاہیے ، اکابر اُمت سے جب ہم کٹیں گے تو پھر ایک آوارہ پتاّ ہی ہو کررہ جائیں گے، ہوا جدھر چاہے گی ہمیں لے جائے گی اور چلو اُدھر کوجِدھر کی ہواہو، کا مصداق بن کر رہ جائیں گے۔پتاّ شاخ کے ساتھ جُڑا ہی اچھالگتا ہے۔ جو پتا شاخ سے ٹوٹ کر گر جائے وہ پھر پاؤں تلے ہی روندا جاتا ہے ۔ یہ نعرہ ، یہ سوچ ، یہ فکر ، یہ نظریہ اور یہ انداز قطعی مناسب نہیں ہے کہ ہم کہتے پھریں ،اکابر کون ہوتے ہیں ؟ ہم اکابر کو نہیں مانتے ۔۔۔ ہمیں اکابر کی راہ نہیں اپنانی ۔۔۔ اور بعض تو اپنی تقاریر میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ موجودہ اکابر کی سوچ اور نظریہ ہمارے جوتے کی نوک پر۔۔۔۔۔۔! یہ تمام الفاظ ، یہ نظریہ اور یہ سوچ ہمار ے ’’باغیانہ پن ‘‘ کی عکاسی کرتے ہیں۔
ہماری ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے ۔ہماری تمام تر عزت ، وقار ، مرتبہ اور مقام اپنے اکابر ہی کا مرہون منت ہے، اکابر ہی سے وابستگی میں ہماری بقا کا رازمضمر ہے ۔ اگرہم اپنے اکابر سے بغاوت کریں گے اور ان سے کٹ کر زندگی گذاریں گے تو پھر:
ہماری داستاں تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں
ہمارا مقصو د یہ باور کرانا بھی نہیں ہے کہ اکابر ’’معصوم‘‘ ہیں ۔ان کی ہربات کوآنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے۔ جہاں ہمیں ان کی رائے اور مؤقف سے اختلاف ہووہاں انتہائی متانت، شائستگی اور ادب واحترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے اختلاف رائے کیا جائے اورا س میں اندازجارحانہ اور گستاخانہ نہ ہو۔ جہاں کہیں کسی معاملہ میں اختلاف ہوتو آپس میں مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر لینا چاہیے ،رسائل وجرائد اور کانفرنسوں میں ان اختلافات کو نہیں اچھالنا چاہیے ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکابرکا مؤقف ہماری رائے کے موافق نہیں اور ہماری سوچ ، فہم اور دانست کے مطابق صحیح نہیں ہے اوروہ بھی اپنے مؤقف کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر خاموشی سے ان سے علٰیحدگی اختیار کرلی جائے اوران اختلافات کو مزید ہوا نہ دی جائے ۔
ہمیں اپنی رائے منوانے پراصرار نہیں کرناچاہیے ،ہم اس کے مکلف قطعاً نہیں ہیں کہ ڈنڈے اور گولی کے زور پر اپنے مؤقف کو منوائیں، جومانتا ہے مانے ، نہیں مانتا نہ مانے ۔ہمارے ذمہ صرف اتنی بات ہے کہ اپنے اس مؤقف اور رائے کی وضاحت ان کے سامنے کردیں ا ور بس۔۔۔!
ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اُچھالنے کے بجائے اگر اصلاح کا پہلو سامنے رکھا جائے تو امید ہے کہ اس کے اچھے نتائج مرتب ہوں گے اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہماری اس درخواست کو درخور اعتنا سمجھاجائے گا اور اس سے بے اعتنائی نہیں برتی جائے گی ۔
(بشکریہ ماہنامہ ’’الحامد‘‘ لاہور)
تنقیدی جائزہ یا ہجوگوئی؟ (۱)
محمد رشید
الشریعہ کے خاص شمارہ (جنوری فروی 2011) کے چار سو صفحے پڑھنے کے بعد پروفیسر میاں انعام الرحمن کے مضمون ’’محاضرات معیشت و تجارت کا ایک تنقیدی مطالعہ‘‘ کا اس ذہن سے مطالعہ شروع کیا کہ ہمیں ایک معیاری،شستہ اور باوقارتنقیدی جائزہ پڑھنے کو ملے گا، لیکن اس تنقیدی مطالعے کے پہلے ہی صفحے میں الفاظ کے استعمال پر ہم کھٹکے، تاہم پھر بھی ہم اسے پڑھتے چلے گئے ۔لیکن ہم بمشکل پانچ صفحے ہی پڑھ پائے تھے کہ بوریت نے ہمارا برا حال کردیا چنانچہ اس کے بعد چھٹا صفحہ پڑھنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہوگیا۔اس کے بعد ہمارا یہ حشر ہوا کہ ہم ہر روزارادہ کرتے کہ آج اس مضمون کو پڑھتے ہیں ، لیکن الشریعہ اٹھانے کو دل ہی نہ کرتا۔اسی آنکھ مچولی میں آٹھ دس دن گزرگئے۔اتوار والے دن ٹھان کر ہی بیٹھے کہ چاہے مضمون کتنا ہی بور لگے، بہرحال ایک دفعہ پڑھنا ضرور ہے۔اور پھر اپنے اس ارادے کوہم نے رات دیر تک عملی جامہ پہنا ہی دیا۔تاہم اس مضمون کے پہلے چھ صفحے ہمیں جتنے بور لگے اگلے ساٹھ صفحے ہمیں اتنے ہی تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ہمیں حیرت ہے کہ مضمون نگار محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ پر تضاد فکری کا الزام بڑے دھڑلے سے لگاتے ہیں لیکن اپنے ہی مضمون کے پہلے ہی صفحے پروہ ڈاکٹر صاحب کے علم و فکر کی جس بلندی کا اقرار کرتے ہیں باقی ساٹھ صفحات میں شد و مدسے سے اس کا انکار کرتے پائے گئے ہیں ،جس کا عروج ان کے مضمون کے آخری صفحے پر ہمیں ملتا ہے۔
مضمون نگار اپنے نام میں ’’پروفیسر میاں‘‘ کے لاحقے کے ساتھ اور الشریعہ کے لکھاری ہونے کی وجہ سے ہمیں جتنے موٹے محسوس ہورہے تھے،اپنے انداز تحریر اور قلم کے استعمال کی وجہ سے وہ ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر چھوٹے محسوس ہوئے۔مضمون نگار کا یہ پہلا مضمون تھا جو ہم نے اپنے ہوش و خرد کو مکمل حاضر رکھتے ہوئے بیک وقت مکمل مطالعہ کر لیا۔ مضمون نگار کے ظرف کا چھوٹا پن ان کے انداز تحریر سے بار بار ٹپک رہا تھا۔اور ہم بار بار افسوس کا اظہار کررہے تھے کہ اے کاش! ایسے ’’چھوٹے‘‘ آدمی سے واسطہ نہ ہی پڑتا تو اچھا تھا۔لیکن ڈاکٹر غازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم استاد کے (غائبانہ ہی سہی)انتہائی حقیر شاگرد ہونے کی حیثیت نے ہمیں پابند کیا کہ ہم ان کے افکارکے تنقیدی جائزہ کا کھلے دل سے جائزہ لیں۔ہم نہایت افسوس سے عرض کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ یہ مضمون ’’تنقیدی و علمی جائزہ ‘‘کم اور’’تحقیری /استہزائی و ادعای‘‘ انداز زیادہ لیے ہوئے تھا۔
ایسا غیر معیاری اور ظرف سے عاری مضمون کسی بھی طرح ایک عظیم شخصیت کی وفات کے موقع پر اس کی یاد میں شائع ہونے والے مضامین میں جگہ پانے کے قابل نہیں۔یا تومدیرالشریعہ نے اس مضمون کو دیکھا ہی نہیں یا پھر الشریعہ کی روایتی اعلیٰ ظرفی نے ایسے گھٹیا مضمون کو غلط موقع پر شائع کرنے کی غلطی کرائی۔ایسا مضمون اگر کسی مباحثے کے دوران شائع کیا جاتا تو بات دوسری ہوتی۔مگرڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ ایسی نہایت اعلیٰ ظرف شخصیت کی یاد میں ایسے ’’کم ظرف‘‘ مضمون کی اشاعت سخت ناانصافی ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ محترم ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید نہیں ہوسکتی۔ بلا ریب ہر علمی و فکری کام کرنے والے کے ’’کام‘‘ کا تنقیدی محاکمہ و تجزیہ ہر اہل علم کا حق ہے مگر تنقیدی محاکمہ اور گھٹیا اتہام بازی میں دور دور تک کوئی رشتہ و ناطہ نہیں۔ پہلی چیز ایک زندہ و باضمیر معاشرے کی نہایت بنیادی ضرورت ہے تو دوسری چیز ایک صالح علمی روایت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔
ہم ذیل میں حضرت انعام کے اس خود ساختہ تنقیدی جائزے کے چند نکات ونتائج کا جائزہ لیتے ہیں۔
۱۔ مضمون نگار محترم غازی صاحبؒ کے محاضرہ کا اقتباس پیش کرتے ہیں جس کا آخری حصہ یوں ہے:
’’من صنع منکم شیئا فلیحسنہ‘‘ کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی چیز بنائے، یادرکھیے کہ یہاں صنعت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں پوری صنعت اور انڈسٹری شامل ہے۔ ’’فلیحسنہ‘‘ تو اس کو بہت خوبصورت اور بہتر انداز سے مکمل کرے ، بہتر انداز سے بنائے۔ یہ صنعت کاروں کے لیے ایک ہدایت ہے کہ تم جو بھی صنعت تیار کرو، جو چیز بھی پیداوار کرنے کے لیے اختیار کرو، اس کو جتنا خوبصورت بناسکتے ہو بناؤ۔‘‘
صاحب محاضراتؒ نے حدیث سے بہت ہی خوبصورت اور عصری زندگی کی راہنمائی کرتے ہوئے ایک بامعنی تشریح کی۔مگر مضمون نگار حضرت انعام اس پر اپنی ’’کم ظرفی‘‘ کا اظہار یوں فرماتے ہیں:
’’اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اب ہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم :’’من صنع منکم شیئا فلیحسنہ‘‘ کو دنیا کے سامنے اس دعوے کے ساتھ پیش کریں کہ دیکھو! تم لوگوں نے صنعتی انقلاب کے بعد اور اس صنعت کی خرابیوں کے ظہور کے بعد غیر موزونیت سے آگاہ ہوکر موزونیت کا عمل شروع کیا ہے، لیکن دیکھو! اسلام نے چودہ سو تیس سال سے بھی پہلے عالم انسانیت کے اس سلسلے میں راہنمائی کی ہے۔ غورکیجئے کہ کیا ہمارے اس دعوے میں کوئی وزن ہوگا؟ اس قسم کے دعوے ہم اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں اور اہل علم ہمیں جاہل قرار دیتے ہوئے خاموشی سے اپنا کام کیے جاتے ہیں۔(خیال رہے یہاں اہل علم مغربیوں کو کہا جارہا ہے)‘‘
نہایت افسوسناک بات ہے کہ حضرت انعام صاحب محاضرات کا ایک خوبصورت اقتباس لے کر پہلے لایعنی تنقیدی تجزیہ پر ایک صفحہ سیاہ کرڈالتے ہیں اور پھر محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم حدیث کے سلسلے میں ایک خوبصورت نکتہ کے خلاف اپنے بغض، استکباراور گھٹیا پن کا اظہار درج بالا اقتباس کے ذریعے کرتے ہیں۔محترم غازی صاحبؒ کا اندازبیان اور نقطہ نظر اورمضمون نگار کا انداز بیان ہردومخالف اقتباسات کو آمنے سامنے رکھ کراس بات کا بخوبی ادراک کیاجاسکتا ہے کہ مضمون نگار نے بڑے ڈرامائی انداز میں محترم غازی صاحب کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے۔ مضمون نگار کے الفاظ اس بات کی چغلی کھارہے ہیں کہ وہ مغرب کی ’’علمیت ‘‘ کے اندھے عقیدے میں مبتلا ہیں اور مغرب کے علمی مغالطوں اور کمزوریوں پراہل مشرق یا اہل اسلام کی طرف سے پیش کی جانے والی بڑی سے بڑی اور مضبوط سے مضبوط دلیل سے بھی وہ اس لیے چڑتے ہیں کیونکہ اہل مغرب’’اصل اہل علم‘‘مسلمانوں کو جاہل قرار دیتے ہیں۔
۲۔ چند سطور کے بعد صاحب محاضراتؒ کے ایک نقطہ نظر پر لایعنی و سطحی تنقید کرنے کے بعد جہاں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں تو یہ انداز بیان اختیار کرتے ہیں:
’’البتہ صرفی قرضوں کی تجویز کی حد تک ڈاکٹر غازی سے سو فی صد اتفاق کرنا پڑتا ہے۔‘‘
انداز بیان پر غور فرمائیں ’’ڈاکٹرغازی سے‘‘ کے الفاظ سے واضح تاثر مل رہا ہے کہ حضرت انعام بے حد بلند و غیرمعمولی مقام کی حامل شخصیت ہیں اور ڈاکٹر غازی مرحوم ایک معمولی درجے کے کوئی مولوی ہیں جن سے حضرت انعام کو ’’اتفاق کرنا پڑرہا ہے‘‘ ۔محترم آپ کے سرپر کیا کسی نے کوئی ڈنڈا اٹھا رکھا ہے ’اتفاق کرنے کے لیے‘‘جس کی وجہ سے آپ کو مجبوراً ’’اتفاق کرنا پڑرہا ہے۔‘‘
اگر انسان کی گفتگو میں ’’باڈی لنگویج‘‘ اور الفاظ کے چناؤ و استعمال کی ترکیب کو خاص اہمیت حاصل ہے تو ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت انعام کا درج بالا اقتباس محترم غازی صاحبؒ کے کسی فکر کی بلندی کا اعتراف نہیں بلکہ ایک معمولی درجے کے مفکرکے مقابلے میں مضمون نگار کا اپنی وسعت ظرفی کا اعلان لیے ہوئے ہے۔
۳۔ اس کے بعد محترم غازی صاحب ؒ کے اقتباس پیش کرنے کے بعد مضمون نگارلایعنی بحث اور تنقید پر صفحے کے صفحے سیاہ کرتے چلے جاتے ہیں۔بالکل ایسے ہی جیسے ’’گھوڑوں کی اصناف‘‘ پرکتاب لکھنے کا دعویدار پہلے صفحے پر ’’گھوڑا دوڑ رہا ہے‘‘ لکھنے کے بعد ہر صفحے پر ’’دغڑ دغڑ‘‘ لکھتا چلا جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا علمی کام کررہا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ مضمون نگار کے ’’تنقیدی جائزہ‘ ‘ کا’’علم و تحقیق‘‘ سے دور دور تک کوئی واسطہ نظر نہیں آتااور تنقید کے مستند اصولوں اور معیارات سے بھی گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ہمارے نزدیک یہ ’’تنقیدی جائزہ‘‘اس سطح کا ہے ہی نہیں کہ اس کاتجزیہ کرنے پر وقت ضائع کیا جائے۔لیکن چونکہ یہ ایک موقر علمی و تحقیقی ماہنامے میں شائع ہوا ہے لہٰذا اس کا محاکمہ کرنے کے تلخ فریضہ کی ادائیگی پر ہم نے اپنے آپ کو مجبور محسوس کیا ہے۔
۳۔ مضمون نگارمحترم غازی صاحبؒ کا کوئی اقتباس پیش کرتے ہیں اور پھر اٹکل پچو اور جذبات کی لٹھ لے کر چڑھ دوڑتے ہیں۔ صاحب محاضرات کا ایک اقتباس درج کرنے کے بعد الشریعہ کے ص ۴۱۹ پریوں رقمطراز ہیں:
’’غالباً ڈاکٹر غازی مرحوم مستضعفین کو قارونی طبقہ کے خلاف بغاوت پر اکسا کر قرآنی نقطہ اعتدال (جسے وہ خود قیام للناس کہتے ہیں) کے ابلاغ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، اسی لیے مستخلفین کو امر واقعی کے انداز میں لے رہے ہیں۔ خیر! یہ کوئی نئی بات نہیں تاریخ بتاتی ہے کہ (شاہ ولی اللہؒ اور کارل مارکس جیسے افراد کے استثنا کے ساتھ) علما اور سکالرز کی اکثریت کا یہی شیوہ رہا ہے۔‘‘
علم و فکر کے توازن کے شاہکار ایک باکردارانسان کی وفات کے موقع پر اسے خراج عقیدت دینے کا یہ نہایت نادر ،بدبودار اورپست انداز پہلی دفعہ حضرت انعام کے مضمون کے ذریعہ ہمارے مشاہدہ میں آیا ہے۔قارئین کرام !درج بالا پیراگراف پر غورفرمائیں اور پھر بتائیں کیا اس کے لفظ لفظ سے ’’نفرت اور حقارت ‘‘ نہیں پھوٹ رہی کہ شاہ ولی اللہ اور کارل مارکس کے سوا علما وسکالرز کی اکثریت بشمول ڈاکٹر غازی قارونی طبقہ کے درپردہ حمایتی اور پشتیبان رہے ہیں۔مضمون نگار کی اس ہجوگوئی کے برعکس محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس فکری حسن اور متوازن نقطہ نظر کے حامل تھے اس کی ہلکی سی جھلک ان کے محاضرات ’’معیشت و تجارت‘‘ کے درج ذیل اقتباسات میں دیکھی جاسکتی ہے۔:
’’قرآن کریم نے ربا کی حرمت کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس پر ایک تفصیلی گفتگو میں بات ہوگی۔مال کو جمع کرنے اور سینت سینت کر رکھنے کی برائی بیان کی گئی ہے۔ مال کو خرچ کرنے کی جابجا تلقین کی گئی ہے۔ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، نادار کی مدد کرنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے میں مدد دینا۔ یہ وہ اخلاقی رویے ہیں جو قرآن مجید مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اخلاقی رویہ محض اجتماعی یا ثقافتی میدان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تعلق انسانوں کے معاشی رویے سے بھی ہے۔ جب انسانوں کے اخلاق و کردار میں بہتری آئے گی، جب انسان مال و دولت کے بارے میں اخلاقی ہدایات کے پابند ہوں گے تو معاشی رویے میں اصلاح خود بخود پیدا ہوگی۔‘‘(محاضرات معیشت و تجارت ۔ صفحہ 31)
’’عدل اور قسط کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی رو سے یہ ریاست کا فریضہ ہے کہ حقیقی انصاف قائم کرنے میں عامۃ الناس کی مدد کرے اور ریاست اپنے وسائل کی حد تک ، اپنے مقدور کی حد تک عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔۔۔۔۔۔۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ جملہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حکومت اور مملکتیں کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں۔ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتیں۔اس لیے کہ ظلم اس دنیا میں بھی تباہی کا موجب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تاریکیوں کا اور ظلمتوں کا سبب ہے۔‘‘ (محاضرات معیشت و تجارت ۔ صفحہ 32)
معلوم نہیں یہ مضمون نگار کی بدنیتی ہے یا کہ بدمذاقی کہ جس صفحے کا ایک اقتباس لے کر وہ استاد محترم پر قارونی طبقہ کی مخالفت سے اعراض کا الزام لگا رہے ہیں،مضمون نگار کے اسی اقتباس سے پہلے اور بعد میں محترم غازی صاحب کے مذکورہ بالا اقتباسات سے اندھوں کو بھی اس چیز کا واضح ادراک ہوجاتا ہے کہ غازی صاحب ؒ قارونیت،ظلم اوراستحصال کے نہ صرف مخالف تھے بلکہ وہ قرآن وسنت اور صحابہ کرام کے حوالہ جات سے اس کا بطلان کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔قارونیت کی مخالفت سے اعراض کرنے کا طعنہ دینے والے ذرا محترم غازی صاحبؒ کا درج ذیل اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیں:
’’۔۔۔قرآن مجید نے فقر و فاقے کے معاملے سے بہت زیادہ اعتنا کیا ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام اسباب کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے، ان تمام راستوں کو بند کرنے کی تلقین کی ہے جن کے نتیجے میں فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فقر کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے وسائل رزق یکساں پیدا کیے ہیں۔ ہر انسان کو دو ہاتھ دے کر بھیجا ہے، ہر انسان کو سوچنے والی عقل عطا فرمائی ہے۔۔۔۔۔۔۔ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تکوینی سے انسانوں کے درمیان بعض پہلوؤں سے تفاوت رکھا ہے۔ لیکن جو بنیادی اسباب ہیں وہ سب کے لیے یکساں طور پر فراہم کیے گئے ہیں۔ ان اسباب کا تقاضا یہ تھا کہ معاشرے میں فقر و فاقہ نہ پیدا ہو۔ معاشرے میں معاشی تفاوت ایک حد سے آگے نہ بڑھے۔
جب یہ تفاوت حد سے بڑھنے لگتا ہے اور غریب اور امیر اور فقیر اور دولت مند میں تفاوت بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے کچھ خارجی اور غیر فطری اسباب ہوتے ہیں۔ یا تو کہیں تقسیم دولت میں عدم مساوات سے کام لیاگیا ہے یا مواقع کی فراہمی غیر یکساں کردی گئی ہے، یا کہیں اور بے انصافی جنم لے رہی ہے یا دولت کا ارتکاز ہورہا ہے یا کچھ لوگ جہالت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ کاروبار اور تجارت کے تازہ ترین طریقوں سے ناواقف رہتے ہیں، یا کسی علاقہ میں امراض پھیل گئے ہیں کہ کچھ لوگ ان امراض کی وجہ سے اپنے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرارہے ہیں۔ یا حلال و حرام میں تمیز ختم ہوگئی ہے جس کی وجہ سے آمدنی بھی ناجائز ہے، اخراجات بھی ناجائز ہیں۔
یہ وہ بڑے بڑے اسباب ہیں جن کے نتیجے میں فقر و فاقہ جنم لیتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک یا متعدد اسباب جب پیدا ہوں گے تو معاشرے میں دولت کی تقسیم متاثر ہوگی ، وسائل کی تقسیم میں گڑبڑ پیدا ہوگی۔ غریب غریب تر ہوجائے گا، دولت مند مزید دولت مند ہوجائے گا۔ قرآن مجید نے ان تمام مسائل کا بہت جامع حل تجویز کیا ہے۔ سب سے پہلا حل قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ تقسیم دولت کا ایک نیا نظام عطا فرمایا۔ ۔۔۔
پھر قرآن مجید نے عدل و انصاف کے قیام پر اتنا زور دیا ہے کہ شاید کسی اور آسمانی کتاب نے اتنا زور نہیں دیا۔ جب معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو بہت سے ایسے اسباب ختم ہوجائیں گے جو دولت کے ارتکاز کا ذریعہ بنتے ہیں، تقسیم دولت میں ناہمواری کو جنم دیتے ہیں۔پھر خود ارتکاز دولت بھی شریعت کی نظر میں ایک بہت بڑی برائی ہے اور اس کا خاتمہ قرآن کریم کی معاشی پالیسی کا ایک اہم نکتہ ہے۔ ’’کی لایکون دولۃ بین الاغنیاء منکم‘‘ یہ سب احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ دولت صرف دولت مندوں میں گردش نہ کرے۔ بلکہ معاشرے کے ہر طبقے میں گردش کرے۔۔‘‘(ایضاً صفحہ35۔36)
’’ان بالواسطہ اقدامات کے ساتھ ساتھ شریعت نے دولت کی وسیع پیمانے پر تقسیم کے لیے کچھ مثبت اور براہ راست ہدایات بھی دی ہیں۔ مثلاً ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کی ہے۔ مثلاً غیر ضروری طور پر بڑے بڑے رقبہ جات کی ملکیت اور ان کو غیر آباد چھوڑنے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ کسی کی زمین کی تین سال تک بغیر آبادی اور کاش کے ملکیت شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اگر سرکاری زمین کسی شخص کو آباد کرنے کے لیے الاٹ کی گئی ہے اور وہ تین سال تک آباد نہ کرسکے تو وہ زمین اس سے واپس لے لی جائے گی۔ اسی طرح سے سرکاری چراتاہوں کے علاوہ ذاتی چراگاہیں یا گھوڑی پال مربعے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بڑے پیمانے پر لوگ رقبوں کو روک لیں اور اپنے جانوروں کے چرنے کے لیے اس کو خالی چھوڑدیں، دوسروں کو استعمال نہ کرنے دیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف سرکاری یا فوجی جانوروں کے چرنے کے لیے جو جہاد میں کام آتے ہوں، حکومت کو اجازت ہے کہ وہ سرکاری چراگاہیں قائم کرے اور وہاں جانوروں کی نسل کشی کا انتظام کرے۔
ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے جگہ جگہ مال کو جمع کرنے کی برائی اور خرچ کرنے کی اچھائی بیان کی ہے۔ مال کو جمع کرنا برا بتایا ہے، خرچ کرنا اچھا بتایا ہے۔ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ہو تو بلاشبہ، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو، وہ اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے خاندان پر، اپنے گھروالوں پر خرچ کرے تو مجرد خرچ کرنا بھی مال کو روک کر رکھنے سے بہتر ہے۔
جب مال کو انسان روک کر رکھتا ہے تو وہ نہ اس کے کام کا نہ کسی اور کے کام کا۔ گھر میں سونے چاندی کے انبار رکھے ہوں تو وہ کس کام کے۔ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں گڑھے کھود کر سونے چاندی کی اینٹیں جمع کرلیتے تھے اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا تھا، بارہا ایسا ہوا کہ کسی شخص نے خاموشی سے دولت جمع کی، اپنے گھر میں دفن کردی اور بعد میں مرگیا۔ کسی کو بتایا نہیں،د ولت ضائع ہوگئی۔ بعد میں کبھی کسی کے ہاتھ لگ گئی تو لگ گئی ورنہ ضائع ہوگئی۔
آج کل پاکستان میں بھی یہی ہورہا ہے۔ بعض بڑے بااثر لوگ ناجائز دولت پاکستان سے حاصل کرتے ہیں اور مختلف فرضی ناموں سے مغربی بنکوں میں جمع کرادیتے ہیں۔ وہ ان کے مرنے کے بعد ضائع ہوجاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی داستانیں وقتاً فوقتاً اخباروں میں آتی رہتی ہیں کہ فلاں گورنر صاحب نے، فلاں وزیر صاحب نے، فلاں بااثر آدمی نے، فلاں ملک کے بنک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، اس میں اتنی رقم تھی اور فلاں نام سے تھی، ان کے مرنے کے بعد وہ ضائع ہوگئی۔ ظاہر ہے کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے۔
یہ ناجائز دولت کے وہ نتائج ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے ارتکاز دولت کو منع کیا ہے۔ قرآن مجید سے یہی پتا چلتا ہے کہ دولت کے حد سے زیادہ پھیلاؤ اور فراوانی کے بہت منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں، جن کی قباحتیں اخلاقی اعتبار سے بہت بری ہیں۔ مترفین کے کرتوت معاشرے کو تباہی کا نشانہ بنادیتے ہیں۔ مترفین سے مراد وہ طبقہ ہے جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، جو دولت کے انبار اپنے پاس رکھتا ہو، دولت کے بڑے بڑے تالابوں پر قابو اس کو حاصل ہوگیا ہواور وہ ان سے کھیلتا ہو۔ جب کسی طبقے میں مترفین کی کثرت ہوتی ہے تو وہاں کثرت سے ایسے فارغ البال اور دولت سے کھیلنے والے وجود میں آجاتے ہیں جن کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، جن کو بے تحاشا دولت بغیر محنت کے مل گئی ہو۔
جب ایسے طبقے کی کثرت ہوتی ہے تو اس سے معاشرے میں بے شمار اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے کا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے۔ معاشرے میں جو نظم اور توازن قائم ہوتا ہے وہ بگڑجاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہوجاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کے حکم تکوینی کی رو سے کوئی بستی تباہ ہوتی ہے تو اس کی فوری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس بستی یا آبادی میں مترفین کی کثرت ہوجاتی ہے۔مترفین اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا فسق و فجور اور ان کے کرتوت اور گناہ پوری بستی کو لے ڈوبتے ہیں۔‘‘(ایضاً صفحہ 45۔46)
’’توازن کی جنتی صورتیں معیشت اور مادیات سے متعلق ہیں، ان کو قائم کرنا اور عدم توازن کو جنم لینے سے روکنا یہ معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے اور ریاست کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب معاشرے سے استحصال کی تمام قوتوں کا خاتمہ کردیا جائے۔ استحصال سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی قوت، دولت، وسائل، اختیارات اور اثر رسوخ سے ناجائز کام لے کر وہ فوائد حاصل کرنا چاہیں جو اخلاقی یا قانونی طور پر ان کو حاصل نہیں کرنے چاہئیں اور دوسرے لوگوں کو ان ضروریات سے محروم کردیں جو ان کی جائز اور بنیادی ضروریات ہیں۔ یہ رویہ استحصال کہلاتا ہے۔‘‘(ایضاً صفحہ102)
قارونیت اور ظلم و استحصال کے خلاف اتنے خوبصورت، سلیس ،متوازن اور پراثر پیرایے میں ابھارنا اور اکسانا یقیناًمحترم ڈاکٹر محمود غازیؒ ہی کی خوبی ہے ، شاید یہی خوبی معترض وہجوگو مضمون نگار کو بری لگتی ہے کہ ڈاکٹر غازیؒ اس موضوع پر لکھتے اور بولتے ہوئے ’’کارل مارکس‘‘ کے الفاظ و اصطلاحات اور اس کے فکر سے مدد کیوں حاصل نہیں کرتے۔
۴۔ محترم غازی صاحبؒ نے تجارت کی فضیلت و اہمیت کے بیان میں ایک حدیث بیان کی۔حضرت انعام کوشاید حدیث سنانے پر بے حدغصہ آیا کہ اتنا بڑا سکالربنا پھرتا ہے اور عقل سے کام لینے کی بجائے موطا کی حدیث سنانے بیٹھ گیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے محترم غازی صاحبؒ کو ان الفاظ میں اپنے نشانے پر لے آتے ہیں: ’’اس اقتباس کا یہ بیان کہ ’’جس طرح چاہے جتنا چاہے اور جتنا نہ چاہے‘‘ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ڈاکٹر مرحوم نے بنا دیا ہے۔‘‘(الشریعہ صفحہ420)
مضمون نگار کا یہ انداز بیان بزبان حال کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر مرحوم ایک سطحی انسان تھے یا پھر سطحیت بیں ہونے کی بناوٹ کیا کرتے تھے۔ کیا ایسے پست انداز فکر کا کوئی علمی جواب دیا جاسکتا ہے؟ہم قارئین سے صرف اتناا عرض کریں گے کہ وہ ’’محاضرات معیشت و تجارت‘‘ کا صفحہ نمبر82اور 83مکمل پڑھ کر بتائیں کہ محترم غازی صاحبؒ اپنے اقتباس میں جو بات کہنا چاہتے ہیں کیا اس پر وہ اعتراض پیدا ہوتا ہے جو ہجوگو مضمون نگار پیدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
۵۔ غازی صاحبؒ مضاربہ کے ضمن میں مغربی دنیا کے بعض تجربات سے استفادہ پر بات کرتے ہیں تو مضمون نگار بھڑک اٹھتے ہیں اور صاحب محاضرات کا اقتباس درج کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے اس عظیم انسان پر یوں نشترزنی کرتے ہیں:
’’مغربی نظام کی افادیت و کامیابی کو ڈاکٹر غازی مرحوم صحیح تناظر میں نہیں دیکھ پارہے‘‘
’’جو بات مغربیوں سے سیکھنے کی ہے ڈاکٹر غازیؒ سمیت ہم میں سے اکثر لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہیں۔‘‘
’’اس لیے ہمیں معاشی ترقی میں مطلوب اخلاقیات (business ethics)کو رواج دینے کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ مغربی طرز کے ظاہری قواعد و ضوابط کی اندھا دھند پیروی کی۔‘‘
مضمون نگار کھینچ تان کر اعتراض کررہے ہیں کہ محترم غازی صاحبؒ کومغربی نظام کا نہ ہی صحیح ادراک ہے اور نہ ہی وہ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وعظ فرماتے ہیں کہ ’’ ہمیں معاشی ترقی میں مطلوب اخلاقیات کو رواج دینے کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ مغربی طرز کے ظاہری قواعد و ضوابط کی اندھا دھند پیروی کی۔‘‘ مضمون نگار سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ جناب غازی صاحبؒ نے کب اور کہاں مغربی طرزکی اندھا دھند پیروی کی دعوت دی ہے؟ اور پھر ’’معاشی ترقی میں مطلوب اخلاقیات کو رواج دینے‘‘ کی جو بات حضرت واعظ انعام صاحب فرمارہے ہیں کیا محترم غازی صاحب نے اپنے محاضرات میں اس اغماض برتا ہے۔ ہمیں نہایت افسوس سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ مضمون نگار نے اپنے مضمون سے شدید ناانصافی اور خیانت کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ نے تو اپنے محاضرات معیشت و تجارت کا آغاز ہی ’’معاشی ترقی میں مطلوب اخلاقیات‘‘ سے کیا ہے اور پھر ان اخلاقی قدروں کو محض معاشی ترقی تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ معاشرے کے تمام شعبوں کی استحکام و ترقی کے لیے انہیں ضروری قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو محاضرات شریعت سے درج ذیل اقتباسات:
’’دوسری اہم بات قرآن مجید کے طالب علم کو یہ ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ قرآن مجید اجتماعی، اقتصادی اور مادی معاملات کے خلاقی اور روحانی پہلوؤں سے زیادہ اعتنا کرتا ہے۔ معاملات کے خالص انتظامی اور دنیاوی پہلوؤں کے مقابلہ میں قرآن پاک کی زیادہ دلچسپی ان امور کے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں سے ہے۔ یقیناًمعاملات کے دنیاوی اور مادی پہلو قرآن کریم نے نظر انداز نہیں کیے۔ لیکن ان سے قرآن کریم کی دلچسپی جزوی ہے۔ قرآن کریم کی اصل دلچسپی معاملات کے اخلاقی او رروحانی پہلوؤں سے ہے۔ ‘‘(صفحہ15)
’’قرآن مجید اور سنت کی توجہ کا مرکز وہ معاشی معاملات ہیں جن میں normativeپہلو بہت نمایاں ہیں۔ دولت کو کیسے حاصل کیاجائے، کہاں خرچ کیاجائے، کیسے خرچ کیاجائے، کون کون سے معاملات جائز ہیں، کون کون سے معاملات ناجائز ہیں۔ کاروبار وتجارت کے بنیادی اخلاقی اصول کیا ہونے چاہئیں۔ انسانوں کا آپس کا لین دین، تجارت اور مالی تعاون کس نہج پر استوار ہونا چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے بنیادی ہدایات دی ہیں۔‘‘(صفحہ16)
’’انسان کے رویے کی تشکیل، انسان کی ذہن سازی، کردارسازی اور اخلاق کی تعمیر، یہ اہداف قرآن مجید کا سب سے بڑا مقصود ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کردار سازی ہوجائے، ایک مرتبہ مناسب رویے کی تشکیل ہوجائے تو پھر یہ رویہ معاشیات میں بھی جھلکتا ہے، سیاسیات میں بھی جھلکتا ہے اور زندگی کے دوسرے تمام پہلوؤں میں بھی نظر آتا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں قرآن مجید اس طرح کے مضامین کو بیان کرتا ہے، وہاں جگہ جگہ کہیں کوئی معاشی انداز کی ہدایت ہے، کہیں کوئی ثقافتی رہنمائی ہےء کہیں کوئی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی ہدایات ہیں۔ کہیں انسانوں کے درمیان آپس کے میل جول اور تعاون کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا جب بار بار اس کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں اور بہت سے حقائق اس کے ذہن نشین ہوجاتے ہیں وہاں اسلام کی معاشی تعلیم کی اساس اور بنیاد بھی اس کے ذہن میں پوری طرح سے راسخ اور مرتسم ہوجاتی ہے۔‘‘(صفحہ17)
۶۔ مضمون نگار کو محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلیٰ اور محفوظ فکر پر بھی شدید اعتراض ہے کہ وہ قرآن و سنت کی نصوص اورقرآن و سنت سے اخذ کردہ فقہائے اسلام کے متفق علیہ قواعدکی پیروی کی بات کیوں کرتے ہیں۔صاحب محاضرات کی اس فکری سلامتی پر وہ منکرین سنت کی طرح اس قدر سیخ پا ہوتے ہیں کہ کئی صفحے اس کی تغلیط پرسیاہ کردیتے ہیں۔صفحہ 435سے 440تک وہ اپنا علامہ پن اسی تسلسل میں بگھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
(جاری)
مکاتیب
ادارہ
(۱)
Dear Ammar Nasir Sahib,
I saw the article, " Sarmaayadarana ya sciencee ilmiyat. Aik ta,aaruf" in your 'is maah kaa intikhab'. I was shocked and when I say I was shocked, this is an understatement. This article is so unreasonable, biased, absurd and senseless that it is not even worth contradicting. Perhaps first time in the history, knowledge has been torn apart on the basis of capitalism and non-capitalism. Science and technology and the concepts of development and equality have been discarded as alien to Islam. But the real shock is that Al Shareea has published this piece of Dogmatism. It proves that it is impossible to get rid of what one 'learns' in madrasa!!! On the one hand, you are publishing articles of Mahmood Ghazi and students of Javed Ghamdi and on the other hand such samples of obscurity are also being dished out! That you published it because you believe in freedom of expression will be a farce. In that case you should accommodate view point of barailvees, sheea and qadyanees also! This unfortunate article can be rejoined but that will be sheer wastage of time.
Your brother in shock,
Muhammad Izhar ul Haq
izhar@izharulhaq.net
(۲)
سوال: فقہا ایسے بہت سے فرقوں کو مسلمان ہی شمار کرتے ہیں جن کے عقائد تو قطعیات اسلام کے خلاف ہوتے ہیں مگر پھر بھی تاویل کی بنا پر وہ تکفیر کی تلوار سے بچ جاتے ہیں۔ (واضح رہے یہاں قطعیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ثبوت قطعی ہو)۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے جہمیوں کے پیچھے نماز پڑھ لینے کی اجازت دی ہے۔ جبکہ قادیانی یوں کہتے ہیں کہ آیت قرآنی ’ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین‘ میں خاتم النبیین، خاتم المرسلین کو مستلزم نہیں اور اسی طرح لا نبی بعدی بھی لا رسول بعدی کو مستلزم نہیں، مگر فقہاے کرام ان پر کفر کا وار ضرور کرتے ہیں۔ اب واضح یہ ہونا چاہیے کہ تاویل کہاں کہاں کام کرتی ہے اور کہاں کہاں نہیں۔ کیا معتزلی، مشبہہ وغیرہ قطعیات کے منکر نہیں تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج کے خلاف جو جنگ کی تو اس کا سبب خارجیوں کے عقائد تھے یا یہ کہ انھوں نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا تو اس کے دفاع میں حضرت علی نے انھیں مارا؟
محمد عبد الرافع
چوک فوارہ۔ ملتان
جواب: آپ کے سوال کے حوالے سے میری گزارشات حسب ذیل ہیں:
کسی گروہ کو جو قطعی نصوص سے ثابت کسی امر کا منکر ہو، تاویل کی رعایت دیتے ہوئے تکفیر سے بچانے کا اصول بالکل درست ہے، تاہم اس کا عملی اطلاق کرتے ہوئے بہت سے دوسرے پہلووں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ قادیانیوں کے معاملے میں امت نے کم وبیش اجماعی طور پر اس اصول کے اطلاق کو درست نہیں سمجھا جس کے بنیادی وجوہ میرے فہم کے مطابق دو ہیں:
ایک یہ کہ تاویل کی رعایت علمی وعقلی طور پر اسی صورت میں دینی چاہیے جب اس بات کا کافی اطمینان ہو کہ منکر دیانت داری کے ساتھ غور کرتے ہوئے فی الواقع کسی شبہہے کی وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ مرزا غلام احمد کے معاملے میں یہ صورت نہیں پائی گئی۔ اول تو نبوت اور نزول وحی کا دعویٰ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جھوٹ اور افترا ہے۔ پھر مرزا صاحب کے ہاں کذب اور افترا اور اخلاقی بد دیانتی کی جو مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتیں کہ ان کے بارے میں کسی حسن ظن سے کام لیا جائے۔ مزید برآں کسی بھی گروہ کی طرف سے پیش کی جانے والی تاویلات خود اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی یہ بتا دیتی ہیں کہ ان میں شبہے کا پہلو کتنا ہے اور عمداً تحریف کا کتنا۔ صدر اول میں جن گروہوں مثلاً جہمیہ وغیرہ اور بعد میں روافض کی تکفیر کے متعلق سلف نے عمومی طور پر جو احتیاط کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نصوص اور واقعات کی تعبیر میں عام انسانی نفسیات اور فہم کے اعتبار سے ایسی گنجائش محسوس کرتے ہیں جو ان گروہوں کے راہ راست سے بھٹکنے کا سبب بنی۔ خود قرآن نے یہود کے لیے’مغضوب علیہم‘ اور نصاریٰ کے لیے ’ضالین‘ کے الگ الگ الفاظ استعمال کر کے اس پہلو کو واضح کیا ہے اور کفر وضلالت میں دونوں گروہوں کے اشتراک کے باوجود قرآن کا لب ولہجہ یہود کے بارے میں بدیہی طور پر زیادہ سخت اور بے لچک، جبکہ نصاریٰ کے معاملے میں نسبتاً نرم ہے۔ قادیانی حضرات کی تاویلات کا معاملہ نصاریٰ سے زیادہ یہود سے مشابہت رکھتا ہے۔ مرزاصاحب اور ان کے حواریوں کی پیش کردہ تمام تاویلات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ نصوص کو خارج میں قائم کردہ ایک مفروضے کے اثبات کے لیے توڑنا مروڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے واضح ترین دلالتوں کو چھوڑ کر دور از کار تاویلات اور احتمالات کا سہارا لینے میں وہ کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتے۔ یہ ساری صورت حال میرے خیال میں اس کا سبب بنی ہے کہ علماے اسلام قادیانی گروہ کے معاملے میں تاویل اور شبہہے کی وجہ سے عدم تکفیر کے اصول کا اطلاق کرنے پر مطمئن نہیں ہوئے اور ان کی تکفیر ہی پر امت کا اتفاق ہو گیا۔
دوسری اہم وجہ وہ اصول ہے جسے علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی تحریروں میں واضح کیا ہے۔ کسی گروہ کو تاویل کا فائدہ دینا اس لازمی شرط سے مشروط ہے کہ وہ گروہ امت مسلمہ کے بنیادی مذہبی تشخص سے ہٹ کر اپنے لیے کسی الگ مذہبی تشخص کا مدعی نہ ہو۔ دنیا کے مذاہب میں امت مسلمہ کا بنیادی مذہبی تشخص جو اسے سماجی اورمعاشرتی سطح پر دوسرے گروہوں سے ممتاز کرتا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک دین کا واحد اور حتمی ماخذ ماننا۔ اگر کوئی گروہ ختم نبوت کے عقیدے میں تاویل کر کے ایک نئے مصدر اطاعت اور ماخذ ہدایت کی بنیاد پر اپنا الگ تشخص قائم کرتا ہے تو وہ غیر تشریعی، ظلی اور امتی نبی کی اصطلاحوں کا کتنا ہی سہارا لے، عملاً وہ اپنے آپ کو ایک نئے مرکز اطاعت سے وابستہ کر دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے باوجود آپ کی تعلیمات کی تعبیر وتشریح میں وہ اس نئے مرکز اطاعت کو حتمی اتھارٹی کا درجہ دیتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات عملاً بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود قادیانی حضرات اپنے اس تصور کی رو سے مجبور ہیں کہ ایمان واسلام کے دائرے کو مرزا صاحب کے معتقدین تک محدود رکھتے ہوئے ان پر ایمان نہ رکھنے والی ساری امت مسلمہ کو ’کافر‘ شمار کریں۔
اس بنیادی نکتے کی حد تک علماے اسلام کے موقف میں بہت وزن ہے۔ البتہ میرے خیال میں اس معاملے میں قادیانی قیادت اور ان کے تاویلاتی جال میں پھنس جانے والے عام سادہ لوح مسلمانوں کے مابین جو فرق حکمت دین کی رو سے ملحوظ رکھا جانا ضروری تھا، وہ نہیں رکھا گیا اور عام لوگوں کو ہمدردی اور خیر خواہی سے راہ راست پر واپس لانے کے داعیانہ جذبے پر نفرت اور مخاصمت کے جذبات نے زیادہ غلبہ پا لیا۔ میرے نزدیک قادیانی گروہ کو قانونی طور پر مسلمانوں سے الگ ایک غیر مسلم گروہ قرار دے دیے جانے سے امت مسلمہ کے تشخص اور اس کی اعتقادی حدود کی حفاظت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے علما اور داعیوں کی محنت اور جدوجہد کا ہدف اصلاً یہ ہونا چاہیے کہ وہ دعوت کے ذریعے سے ان عام قادیانیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے حوالے سے قادیانی قیادت کا مفاد بھی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں سے الگ تھلگ اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ناواقف رہیں اور معلوم نہیں کن ضرورتوں یا مجبوریوں کے تحت ہماری مذہبی قیادت بھی انھیں مسلمانوں سے دور ہی رکھنے کو اپنی ساری جدوجہد کا ہدف بنائے ہوئے ہے۔
محمد عمار خان ناصر
۱۱؍ دسمبر ۲۰۱۰ء
تعارف و تبصرہ
پروفیسر میاں انعام الرحمن
’’قلم کے چراغ‘‘
برِ عظیم پاکستان و ہند کی مزاحمتی تاریخ جن قدآور شخصیات کے ذکر کے بغیر ہمیشہ ادھوری سمجھی جائے گی، ان میں ایک بڑا نام آغا شورش کاشمیری مرحوم کا ہے۔جن لوگوں نے آغا صاحب کا عہد دیکھا ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس فانی دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اب ایسی محافل ایسی مجلسیں اور ایسی نشستیں کبھی کبھار ہی منعقد ہوتی ہیں جن میں آغا شورش کی شخصی خوبیوں اور ان کے کردار کے متعلق گفتگو ہوتی ہو، انگریز سامراجیت سے ان کی نفرت و حقارت کا بیان ہوتا ہو، ایوبی آمریت کے خلاف ان کی للکار یاد کی جاتی ہو اور ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر ان کی ولولہ انگیزیوں کا تذکرہ ہوتا ہو۔ ہمیں بارہا تجربہ ہوا کہ جب بھی نئی نسل کے سامنے آغا شورش جیسے حریت پسندوں کا نام رکھا گیا تو ’انہیں‘ ہمیشہ نامانوس اور ناواقف ہی پایا۔ اس فقرے میں ’انہیں‘ سے مراد صرف نسلِ نو نہیں ہے بلکہ حریت پسند بھی اس میں شامل ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ دونوں دو مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں حیرت کے سائے ہیں۔ حریت پسندوں کی نگاہوں میں البتہ ایک سوال بھی ہے کہ ہم نے قربانیاں ایک ایسی نسل کے لیے تو نہیں دی تھیں جو تاریک راہوں میں(تقریباً) ماردی گئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، غرض ہر وقت موبائل رہتا ہے۔ جس کا اوڑھنا بچھونا اسی قسم کی لا یعنی فضول سرگرمیاں ہیں۔ دوسری طرف ایک سوال نئی نسل کی آنکھوں میں بھی ہے کہ آخر تم ہو کون ؟ یہ سوال بخوبی وضاحت کر رہا ہے کہ ایک خلیج ہے جو عہدِ رفتہ کی لطافتوں اور عہد حاضر کی کثافتوں کے درمیان وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ زبان و ادب کے ذریعے اس خلیج کو پاٹنے کی امید رکھنے والے نا امیدی کے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں کہ زبان سے بڑھتی ہوئی بیگانگی آخر کہاں جا کے تھمے گی؟ کیا نوبت اشاروں کی زبان تک آ جائے گی؟اگر زبان و ادب میں ایسا معکوس سفر ہی ہمارا مقدر ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے پرشکوہ ادب کو اشاروں کے سانچے میں کون ڈھال پائے گا؟اس لیے آسان راستہ یہی ہے کہ اپنا مقدر بدلنے کی جدوجہد کی جائے، رجعت قہقری کی راہ میں کم از کم ایسے سپیڈ بریکر قائم کر دیے جائیں کہ یہ سفر رکنے نہ پائے تو چلنے بھی نہ پائے:
جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر
یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی
پروفیسر محمد اقبال جاوید صاحب زمانے کی تیز ہوا کو خاطر میں لائے بغیر نئی نسل کے روبرو ہوئے ہیں۔ انہوں نے ’’قلم کے چراغ‘‘ کے عنوان سے شورشِ رفتہ کا سراغ لگایا ہے اور خوب لگایا ہے، لیکن ان کی تمام جستجو، کھوئے ہوؤں کی آرزو سے لبریز نہیں ہے۔ شاید اسی لیے پروفیسر صاحب نے اپنی محنت شاقہ ، حوالہ جات کے استناد کے سپرد نہیں کی۔ ہمیں تو اس میں شاعرانہ افتاد دکھائی دے رہی ہے۔ شاعر حضرات اپنی کوئی بہت اچھی مطبوعہ یا غیر مطبوعہ نظم اپنے مجموعہ کلام میں جان بوجھ کر شامل نہیں کرتے کہ اپنے تئیں عظیم شاعر ہونے کے زعم میں مستقبل کے کسی ادبی محقق سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس نظم کو دریافت کر کے اپنی خوش بختی کو آواز دے گا اور ایسی جان لیوا بحث چھیڑے گا جس سے بڑے بڑے نقاد چاہتے ہوئے بھی لا تعلق نہیں رہ سکیں گے اور یوں شاعر موصوف ایک ادبی نزاع کے باعث امر ہو جائیں گے۔ اس جملہ معترضہ سے قطع نظر پروفیسرمحمد اقبال جاوید صاحب کو داد دیے بنتی ہے کہ انہوں نے ’چٹان‘ میں مدفون ایک خزانے کے اِدھر اُدھر بکھرے آثار و باقیات کا نہ صرف سراغ لگایا ہے بلکہ خوش سلیقگی سے اس کی سنبھال کا انتظام بھی کیا ہے۔ ’’قلم کے چراغ‘‘ میں ستائیس موضوعات کے تحت آغا شورش مرحوم کے خیالات کو اس طرح سمویا گیا ہے کہ شورشؔ کے بانکپن، جرات، بے باکی اورمخصوص اسلوب و ادا سے قاری کما حقہ آگاہ ہو جاتا ہے۔
زیرِ نظر کتاب میں حرفِ آغاز کے بعد ’چراغوں کی لو سے ستاروں کی ضو تک‘ اور ’آگہی کے چراغ‘ غیر ضروری اضافہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے بجائے شورشؔ کا ایک مفصل سوانحی خاکہ شاملِ اشاعت ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ البتہ شورشی اقتباسات سے قبل، پروفیسر محمد اقبال جاوید صاحب نے ’غبارِ تیرہ شبی میں چراغوں کی روشنی‘ کے عنوان سے محمد حسین آزادؔ سے شورشؔ کا شمیری تک، مخصوص نثری ارتقا سے روشناس کرواتے ہوئے شورشؔ کے پیش روؤں کے نثری شہ پاروں کا جو خوبصورت گل دستہ پیش کیا ہے، وہ خاصے کی چیز ہے۔ اس خوبصورت گل دستے نے رنگا رنگی اور ہما ہمی کا سماں باندھ دیا ہے۔ پھر بھی یہ بات قابلِ بحث ہو سکتی ہے کہ ان چراغوں کی روشنی سے تیرہ شبی کا غبار کہاں تک چھٹا ہے؟ لیکن یہ طے ہے کہ اس روشنی نے شورشؔ کے سوانحی خاکے کی کمی کا احساس مزید بڑھا دیا ہے۔ بہرحال، آئیے اس روشنی کی روشنی میں شورشؔ سے ملاقات کیجیے:
’’ان کے قلم کی کاٹ پر جہاں مخالف کراہتا تھا وہاں انداز و اسلوب کے حُسن پر سر بھی دُھنتا تھا اور یہ خوبی صرف شورش میں تھی کہ ان کا وار کاری ہونے کے ساتھ ساتھ حسین بھی ہوتا تھا۔ ......... ان کی سیاسی نظموں میں بھرتی کے اشعار اور خیالات بالکل نہ ہوتے تھے۔ وہ طویل ترین نظمیں بھی کہتے۔ مگر خیالات میں روانی اس قدر ہوتی تھی کہ آورد کا شائبہ بھی نہ ہوتا تھا۔ آج کوئی مدیر ایسا نہیں جو نثر کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل میں بھی حالاتِ حاضرہ پر نقد و نظر کر سکتا ہو۔........ شورشؔ نے صحافت کو ادب کا بانکپن اور شعر کا حُسن عطا کیا۔....... انہوں نے اپنے پرشکوہ انداز میں بہت سی نظمیں اور ترانے لکھے، وہ مختلف ہئیتوں میں قلم اٹھاتے، سنگلاخ زمینوں میں تغزل کے پھول کھلاتے اور سرفروشانہ جذبوں کو ابھارتے تھے۔........ شورشؔ کے قلم نے ہر تالیف کو ایک ادب پارہ بنا دیا ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے شورشؔ کے خاص اسلوب کا۔ جس میں ندرت کی شگفتگی اور جدت کی شادابی دونوں پائے جاتے ہیں۔ مراد الفاظ و تراکیب کا طنطنہ نہیں بلکہ اسلوب و ادا کا وہ خاص پہلو ہے جس کے دریچے سے قلم کار کی اپنی شخصیت گاہے چھپی ہوئی اور گاہے جھلکتی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی کتابوں کے جو اشتہار چٹان میں دیا کرتے تھے وہ بھی شعر و ادب کا ایک ایسا شہ پارہ ہوتے تھے کہ قاری خودبخود کتاب کی جانب کھنچ کے رہ جاتا تھا۔.....آغا شورشؔ کاشمیری ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ ان کی نثر کے بارے میں کوئی ’ادبی فتویٰ‘ نہیں دیا جا سکتاکہ وہ حدی خواں ہیں یا رجز خواں، طناز ہیں یا مزاح نویس، انشائیہ نگار ہیں یا صحیفہ طراز، شاعر ہیں یا خطیب۔یوں معلو م ہوتا ہے کہ ان میں ہر رنگ موجود ہے۔ ان کی تحریر میں مزاح سے زیادہ طنز کی کاٹ ہے۔ وہ لکھتے لکھتے اداریے کو بھی انشائیے کا نہیں بلکہ انشا پردازی کا روپ دے دیتے ہیں۔ وہ شاعری میں خطابت، خطابت میں شاعری اور نثر میں نظم کہتے چلے جاتے ہیں۔‘‘ (قلم کے چراغ:ص۲۶،۳۰،۳۱،۳۹،۵۸)
آغا شورشؔ کاشمیری کی خطابت کے متعلق پروفیسر اقبال جاوید صاحب کی اس رائے سے اختلاف کرنا کافی مشکل ہے کہ وہ احرار کے گم شدہ قافلے کی آخری کڑی تھے۔ شورشؔ کی خطابت کے اعتراف میں امیرِ شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل الفاظ ایک سند سے کم نہیں ہیں:
’’معلوم ہوتا ہے اس کے حلق میں گراریاں لگی ہوئی ہیں، خدا کا شکر ہے، آواز میں غنا نہیں، ورنہ ہم لوگ چوکڑی بھول جاتے۔ مطمئن ہوں کہ میرا بڑھاپا، جوان ہو گیا ہے۔ میں برگد کا درخت نہیں کہ اس کے نیچے دوسرا پود ا اُگ ہی نہیں سکتا ، شورشؔ میری مراد ہے۔‘‘ (ص۳۸)
شاہ صاحب کی یہ بات کہ ’میں برگد کا درخت نہیں کہ اس کے نیچے دوسرا پود ا اُگ ہی نہیں سکتا‘ ان کی وسعتِ قلبی کی دلیل تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایسے نام نہاد راہنماؤں کے لیے راہنمائی بھی لیے ہوئے ہے جو اپنے تئیں برگد بنے بیٹھے ہیں اور بتکلف نئے پودوں کو اگنے سے روک رہے ہیں۔سطورِ ذیل میں ملاحظہ کیجیے کہ شاہ جی کی مراد نے ایسے دل آویز اسلوب میں انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا ہے جس سے زبان و بیان کا وہ پیرایہ سامنے آتا ہے جس کی بابت تصریحاً کہا جاتا ہے کہ الفاظ شورشؔ کے حضور، قطار اندر قطار صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور موصوف انہیں چن چن کر طلاقت لسانی کا اظہار کرتے ہیں:
’’ کالی داس نے عورت کے روپ کی تصویر کھینچتے ہوئے کائنات کی جن تصوری اور نظری خوبصورتیوں کو یکجا کیا ہے، ان تمام خوبصورتیوں کا مرقع شاہ جی کی خطابت ہے۔ رعد کی گونج، بادل کی گرج، ہوا کا فراٹا، فضا کا سناٹا، صبح کا اجالا، چاندنی کا جھالا، ریشم کی جھلملاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، گلاب کی مہک، سبزے کی لہک، آبشار کا بہاؤ، شاخوں کا جھکاؤ، طوفان کی کڑک، سمندروں کا خروش، پہاڑوں کی سنجیدگی، صبا کی چال، اوس کا نم، چنبیلی کا پیرہن، تلوار کا لہجہ، بانسری کی دھن، عشق کا بانکپن، حسن کا اغماض اور کہکشاں کی مسجع و مقفع عبارتیں انسانی آواز میں ڈھلتے ہی جو صورت اختیار کرتی ہیں، اس کا مرقع شاہ جی کی ذات ہے۔‘‘ (ص۵۶)
پروفیسر محمد اقبال جاوید شورشؔ کی خطابت و طلاقت کے اعتراف میں ایک اور سند پیش کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے:
’’مسجد شہید گنج کی بازیابی کے لیے سول نافرمانی کا آغاز ہوا تو مولانا مظہر علی اظہرؔ نے دہلی دروازے کے باہر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ انہیں الوداع کہتے ہوئے شورشؔ نے ایک تقریر کی۔ یہ تقریر شورشؔ کی اولین تقریروں میں سے تھی۔ اس تقریر کو ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی سنا۔ ان کے تاثرات شورشؔ کے فنِ خطابت پر ایک بھر پور تبصرہ ہیں اور حرفِ آخر بھی:
’میں نے ۱۹۱۹ سے اس زمانے تک بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں سنی تھیں، مگر یہ تقریر کچھ اور شے تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک نوجوان (بلکہ نوخیز لڑکا) خطابت کے طوفان اٹھا رہا تھا۔ الفاظ کی فراوانی، ترکیبوں کی کثرت، جوش کا وفور، طنز کی تیزی، ہجو کی کاٹ، اشعار کی پیوند کاری....... ایک تماشائے لفظ و معنی تھا جو ہر سننے والے کو مسحور و مبہوت کر رہا تھا...... میری نگاہ کا شورشؔ سے یہ پہلا تعارف تھا اور تعارف کیا تھا، ایک شب خون تھا جس نے شورشؔ کے متعلق میرے دل میں ایک مرعوب کن تصور پیدا کر دیا اور یہ تصور عمر بھر رہا۔‘‘(ص۳۸،۳۹)
دارالکتاب، اردو بازار لاہور کے حافظ محمد ندیم صاحب مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ’قلم کے چراغ‘ نہایت اہتمام سے شائع کی ہے۔ متن خوانی تسلی بخش ہے، لیکن ندیم صاحب نے سرورق پر زیادہ توجہ صرف نہیں کی اور نہ ہی ستائیس موضوعات کے بکھراؤ کے سبھاؤ کے لیے اشاریے کا بندوبست کرنے کی زحمت گوارا کی ہے۔ کتاب کے آخر میں ایسا مختصر لغت بھی قابلِ اعتنا نہیں سمجھا گیا جو نئی نسل کے لیے ’قلم کے چراغ‘ کے جملہ مندرجات سہل بناتا ہو۔
’’الاقتصاد‘‘
مسلمانوں کو عالمی برادری میں باعزت مقام دلوانے کے لیے اس وقت بہت سے محاذوں پر کام ہو رہا ہے۔ کہیں عسکریت پنپ رہی ہے اور کہیں مکالمہ و مباحثہ فروغ پا رہا ہے۔ عسکریت اور مکالمے جیسے محاذوں پر ہونے والے کام کا سنجیدگی اور گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آزاد روی اور نفسیاتی صحت مندی کے ساتھ ہونے والا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود ان محاذوں پر ڈٹے ہوئے لوگ لائقِ تحسین ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے تئیں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ ایسے ناگفتہ بہ حالات میں مسلم سوسائٹی میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دین کے تحفظ کے نام پر دقیانوسیت سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ تیر کمان سے ڈرون گرانے کے خواہش مند ہیں۔ پرانی منطق و فلسفے سے آسٹرو فزکس اور حیاتیاتی دریافتوں کو پچھاڑنے کا عزم رکھتے ہیں اور نام نہاد قوتِ ایمانی سے سودی نظام کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے مسلم سوسائٹی کی غالب اکثریت کو فکری طور پر یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ایسی اندوہ ناک صورتِ حال میں اگر اصحابِ فکر و دانش، یرغمالی معاشرت کی نجات کی خاطر درست سمت میں کوئی قدم اٹھائیں تو اسے بآسانی تپتی دھوپ میں تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا جا سکتا ہے۔ حکمتِ قرآن انسٹی ٹیوٹ کراچی کے زیرِ اہتمام ششماہی ’الاقتصاد‘ کا اجرا تازہ ہوا کا ایسا ہی جھونکا ہے جس سے حبس زدہ موسم کے کُھلنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کتاب اللہ میں پوشیدہ معاشی حقائق کی دریافت، عصرِ حاضر کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ ’الاقتصاد‘ نے درحقیقت اسی چیلنج کو قبول کیا ہے۔ اگر تسلسل ، معیار اور آزاد روی کے ساتھ ’الاقتصاد‘ جاری رہا تو امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں، جدید اقتصادی مسائل کے حل کے لیے قابلِ عمل پروگرام تشکیل پا سکیں گے۔
الاقتصاد کا آئندہ شمارہ ’زمین کی ملکیت‘ کے بارے میں ہو گا۔ اس سلسلے میں محققین اپنی نگارشات ’حکمت قرآن انسٹی ٹیوٹ، سندھی جماعت کو آپریٹوہاؤسنگ سوسائٹی، جوگی موڑ، نیشنل ہائی وے، کراچی۷۵۰۳۰‘ کے پتہ پر ارسال کر سکتے ہیں۔ ای میل: hikmatequran@gmail.com
طب مشرق کی مسیحائی
حکیم محمد عمران مغل
میڈیکل سرجری نے ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بہت سے ناقابل علاج امراض آج سائنس کے سامنے رفوچکر ہوتے نظر آنے لگے ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ بہت بھیانک ہے۔ ایلوپیتھک طریق علاج کے مابعد اثرات کی وجہ سے آج انسان متبادل کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ دوسری طرف طب مشرق کے حاملین کی حالت علمی لحاظ سے نہایت ناگفتہ بہ ہے۔ اس میں حالات کا بھی بہت عمل دخل ہے اور کالے انگریزوں کا خفیہ ہاتھ دور تک پہنچا ہوا ہے۔ جدید طبی علوم سیکھنے والے پر ابتدا سے انتہا تک لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد وہ عیش وعشرت میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے جبکہ طب مشرق کے طلبہ کو کوئی پوچھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ ایک طبیب کو فراغت کے بعد سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اسے طب کو ہی الوداع کہہ دینا پڑتا ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود وہ عملی زندگی میں قدم نہیں جما سکتا۔ اس کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے نہ تجربہ اور نہ ایسی حالت کہ موجودہ سوسائٹی اس کو قبول کرے۔
میں نے پرانے اطبا کے چراغوں سے اپنی حکمت کا چراغ روشن کیا ہے، مگر پھر بھی معاشرے کی تیکھی نظریں مجھے گھائل کر دیتی ہیں۔ اطبا کے خلاف عجیب عجیب باتیں سن کر دل کے زخم ہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود، حقیقت خود کومنوا ہی لیتی ہے اور یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ:
یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی
آج بھی ملک کے طول وعرض میں اطبا اپنے مطب چلا رہے ہیں اور بعض دفعہ ایسے حیران کن واقعات سننے میںآتے ہیں جن پر بڑے بڑے معالج انگشت بدنداں ہیں۔ لقوے کی ایک مریضہ کا ناقابل یقین واقعہ سنیں۔ ان کے میاں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں سی ایم ایچ میں اساتذہ کرام کا استاذ ہوں۔ میری اہلیہ پر دوسری بار لقوہ کا حملہ ہوا ہے اور پہلے حملے کے اثرات بھی زبان پر نمایاں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس کس سے علاج کرایا ہے؟ فرمانے لگے کہ تمام متعلقہ ڈاکٹر صاحبان میرے وفادار شاگرد ہیں۔ انھوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، مگر اب دوسرا حملہ ہو چکا ہے۔ دوران کلام میں، مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ گومگو کی کیفیت میں ہیں کہ اطبا کی لن ترانیوں سے خوب واقف تھے اور میری حالت دیکھ کر بھی کچھ سہمے ہوئے تھے اور ڈرتے تھے کہ باقی ماندہ صحت کا سفینہ بھی کہیں بیچ بھنور میں ڈوب نہ جائے۔
میں نے کہا کہ کوئی امر مانع نہ ہو تو نبض اورحالات سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ چل کر نبض دیکھ لیں۔ نبض دیکھی، مطلوبہ سوالات کر کے بیماری کی تہہ تک پہنچا۔ مریضہ کی رنگ حد درجہ کالی ہو چکی تھی۔ ماضی میں کچھ امراض کا مجھے شک ہوا تو میرے پوچھنے پر انھوں نے بتایا کہ ہاں، یہ امراض لاحق رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جن معالجین کرام نے آپ کا علاج کیا ہے، بہت ممکن ہے کہ میں ان کے پایے کا نہ ہوں، پھر بھی میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ پرہیز کریں تو ان شاء اللہ لقوہ ہمیشہ کے لیے نیست ونابود ہو جائے گا۔ خور ونوش کے پرہیز کے علاوہ ایسا کمرہ ہونا چاہیے جس میں کہیں سے روشنی نہ آئے، نہ بلب روشن کریں اور نہ ہی ہوا کا گزر ہو۔ تمام ضروریات زندگی کمرے کے اندر ہی پوری کریں۔ دوا دے کرمیں نے نتیجے کابے تابی سے انتظار کیا۔ ایک ہفتے کے بعد ان کے میاں نے کہا کہ جو حملہ آج سے چھ سال پہلے ہوا تھا، اس کا بھی نام ونشان ختم ہو گیا ہے اور صحت کی خوشی میں کل ہم نے جشن منانا ہے۔
میں نے اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ادا کیا۔ یہ تھی ریٹھے کی مسیحائی جس نے مریضہ کی رنگت نکھاری اور اس کی جان بچائی۔ یوں میرے علاج معالجہ نے اپنی قیمت پائی۔
اگست ۲۰۱۱ء
شریعت کے متعلق معذرت خواہانہ رویہ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
ہفت روزہ ’’اردو ٹائمز‘‘ نیو یارک میں ۲۱؍ جولائی ۲۰۱۱ء کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ :
’’شریعت کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ ایک طرز حیات ہے۔ اگر امریکہ میں شرعی قوانین کے خلاف کوئی قانون بنایا گیا تو اس سے امریکہ کے سیکولر تصور کو دھچکا لگے گا۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر طارق رمضان نے، جو حسن البناءؒ کے نواسے بھی ہیں، نیو یارک میں ’’اکنا‘‘ کے زیر اہتمام ایک فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس کا انعقاد مقامی ہوٹل میں گزشتہ اتوار کو کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر طارق رمضان نے کہا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں شرعی قوانین کو خلاف قانون قرار دینے کی مہم چلائی جا رہی ہے اور پروپیگنڈے کو اسلام کے خلاف ایک نفسیاتی حربے کے طو رپر استعمال کیا جا رہا ہے، مگر یہ کوئی منطقی بحث نہیں ہے، کیونکہ قانون الگ ہے اور شریعت الگ۔ قانون کسی مقصد کو حاصل کرتا ہے، جبکہ شریعت ایک راستے کی نشان دہی کرتی ہے۔ شریعت سزائیں نہیں بتاتی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب شریعت ہیں۔ ڈاکٹر طارق رمضان نے کہا کہ کچھ لوگ صوفی کو شریعت سے ماورا قرار دیتے ہیں، مگر شریعت کے بغیر کوئی صوفی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے جو شریعت کی غلط توجیہ کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں انصاف کے بغیر امن کا تصور مشکل ہے۔ امریکی قانون کئی مسلم ممالک کے مقابلے میں زیادہ انصاف کی ضمانت دیتا ہے اور یہاں مسلمانوں کو ہی نہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادیاں حاصل ہیں۔ یہی شریعت ہے۔ ہر وہ چیز جو صحیح ہے، شریعت ہے۔ صرف مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی قانون لایا گیا تو وہ ایک کالونیل سلوک ہوگا۔ ڈاکٹر طارق رمضان نے کہا کہ جس طرح امریکی آئین نے ریاست اور چرچ کو الگ الگ خانوں میں رکھا ہے، اگر کوئی عورت پریسٹ نہیں بن سکتی تو امریکی آئین ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اسی طرح ہمارے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کسی بھی ایسے قانون کے خلاف مزاحمت کریں گے جس کے تحت مسلمانوں کو معاشرے سے الگ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تقریب میں ڈاکٹر زاہد بخاری سمیت دیگر خواتین وحضرات بھی موجود تھے۔‘‘
مغربی دنیا میں اس طرح کے ملے جلے افکار ونظریات کا عام طو رپر اظہار کیا جاتا ہے، مگر ہمیں دو باتوں نے اس خبر کی طرف بطور خاص متوجہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ جس تقریب میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، وہ ’’اکنا‘‘ (اسلامک سرکل آف نارتھ امریکا) کی سالانہ تقریب تھی اور ’’اکنا‘‘ جماعت اسلامی کے ساتھ فکری ونظریاتی تعلق رکھنے والے حضرات پر مشتمل ہے، جبکہ اظہار خیال کرنے والے محترم دانش ور الشیخ حسن البناءؒ کے نواسے ہیں جو ’’الاخوان المسلمون‘‘ کے بانی تھے۔ ڈاکٹر طارق رمضان موصوف نے مذکورہ رپورٹ کے مطابق ا س تقریب میں جو کچھ فرمایا ہے، ان دونوں نسبتوں کے حوالے سے اس کی بعض باتیں محل نظر ہیں جو اگر جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون کے اب تک چلے آنے والے موقف میں کسی تبدیلی کی غماز نہیں ہیں تو ان کی مناسب وضاحت ان حلقوں کی طرف سے سامنے آنی چاہیے۔ البتہ اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔
جہاں تک ’’سیکولرازم‘‘ کا تعلق ہے، ہمیں اب تک یہی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ مذہبی معاملات میں عدم مداخلت کا نام ہے جس کا مقصد ریاست کو مذہبی معاملات میں مداخلت سے روکنا اور تمام مذاہب کے پیروکاروں کو مذہبی آزادیاں فراہم کرنا ہے، لیکن امریکہ سمیت بہت سے سیکولر ممالک کی پالیسیوں کے تسلسل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس ’’مذہبی آزادی‘‘ اور ’’ریاست کی عدم مداخلت‘‘ کے پیچھے اصل مقصد اسلامی ثقافت وروایات کے عالمی سطح پر دوبارہ اظہار کو روکنا ہے، اس لیے یہ عدم مداخلت دھیرے دھیرے اسلامی روایات کے خلاف مداخلت کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے اور امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ’’اسلامی شرعی قوانین‘‘ کے حوالے سے جس منفی مہم کا خدشہ ڈاکٹر طارق رمضان نے ظاہر کیا ہے، وہ بھی اسی پس منظر میں ہے۔
ہمارے خیال میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ اور جرمنی کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کی شکست وریخت کے موقع پر ترکی کی قومی خود مختاری اور ریاستی تشخص کو تسلیم کرنے کے لیے مغربی ممالک نے شرعی قوانین کی منسوخی اور خلافت اسلامیہ کے خاتمہ کی جو شرط عائد کی تھی، اسے مغربی دنیا میں پورے عالم اسلام کے ساتھ اجتماعی معاہدہ سمجھا جا رہا ہے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں شریعت کے نفاذ کو اس معاہدہ کی خلاف ورزی تصور کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق برطانوی وزیر اعظم مسٹر ٹونی بلیئر نے اپنے دور اقتدار میں پورے اہتمام کے ساتھ اس امر کا اعلان کیا تھا کہ دنیا کے کسی خطے میں خلافت قائم نہیں ہونے دی جائے گی اور نہ ہی شریعت نافذ ہونے دی جائے گی۔
ہمارے بہت سے دانش وروں نے ابھی تک مغرب کے سیکولر ازم کو ’’مذہبی معاملات میں عدم مداخلت‘‘ ہی تصور کر رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اسلام کو ’’نظام حیات‘‘ اور شریعت کو ’’قانونی ڈھانچہ‘‘ قرار دینے کے بارے میں گومگو حتیٰ کہ بعض صورتوں میں نفی کا رجحان اپنائے ہوئے ہیں جو اگرچہ موجودہ عالمی نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی نیت سے ہو سکتا ہے، مگر اصلاً یہ ایک غیر فطری اور غیر واقعاتی سوچ ہے، اس لیے کہ نہ تو مغرب کا سیکولرازم مذہب کا عملی وجود قبول کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کا مجموعی دائرہ سسٹم اور قانونی ڈھانچے سے خالی ہے، کیونکہ اگر اسلام قرآن کریم، سنت نبوی اور خلافت راشدہ سے عبارت ہے تو اس میں ریاستی سسٹم بھی ہے، قانونی نظام بھی ہے اور باقاعدہ احکام وقوانین کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ بھی موجود ہے جس پر عمل درآمد کسی باقاعدہ نظام اور قانونی ڈھانچے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے نظام خلافت کے قیام کے وجوب کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ قرآن کریم کے بہت سے احکام پر عمل درآمد باقاعدہ ریاست کے قیام اور حکومت کے وجود پر موقوف ہے، اس لیے خلافت اسلامیہ کا قیام امت مسلمہ کا اجتماعی دینی فریضہ ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دانش وروں کو اس حقیقت کا اب تو ادراک کر ہی لینا چاہیے کہ حالات بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تذبذب اور گومگو کی کیفیت کا زمانہ بیت چکا ہے، سامنے نظر آنے والے بہت سے واقعات کے پس پردہ اصل حقائق رفتہ رفتہ منکشف ہوتے جا رہے ہیں اور دو سو سال قبل جس فکری اور ثقافتی کشمکش کا آغاز ہوا تھا، وہ اب آخری اور فیصلہ کن راؤنڈ کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے دینی حلقوں سے ’’اجتہاد‘‘ کا مسلسل تقاضا کرنے والوں کو خود بھی ’’اجتہادی نظر‘‘ سے کام لیتے ہوئے اپنا انداز فکر تبدیل کرنا چاہیے۔ مغرب کا معاشی اور معاشرتی نظام ہچکولے کھا رہا ہے اور دینی وروحانی اخلاقیات سے عاری مادہ پرستانہ مغربی فلسفہ حیات کے ناخدا خود متبادل کی تلاش میں پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ وقت اسلام کے نظام زندگی ہونے اور شریعت کے قانون ہونے کی نفی کا نہیں، بلکہ اس کے اثبات واظہار کا ہے اور اقبالؒ کے بقول آج کا مجتہد اور مجدد یعنی اسلامی حکمت ودانش کا اصل وارث وہی ہوگا جو اسلامی اصول وروایات اور احکام وقوانین کو آج کی زبان واسلوب میں پیش کرے گا اور منطق واستدلال کے ساتھ آج کے عالمی قوانین پر ان کی برتری ثابت کرے گا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیوسٹن (امریکہ) سے شائع ہونے والے عربی جریدہ ’’المدار‘‘ کی ایک خبر (۲۹؍ جون ۲۰۱۱ء) کے مطابق ڈاکٹر طارق رمضان کے اصل وطن یعنی عرب جمہوریہ مصر میں حال ہی میں ابھرنے والی عوامی تحریک ’’الحریۃ والعدالۃ‘‘ کے ایک مسیحی راہ نما ناجی نجیب نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں اسلامی شریعت کے قوانین نافذ کیے جائیں۔ انھوں نے کہا ہے کہ نفاذ شریعت سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ:
لا خوف من تطبیق الحدود الاسلامیۃ فاذا کان السارق جزاء ہ ان تقطع یدہ فلتقطع والقاتل یقتل
’’حدود شرعیہ کے نفاذ سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب چور کی سزا ہی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیاجائے تو وہ کٹ جانا چاہیے اور قاتل کو قصاص میں قتل ہونا چاہیے۔‘‘
ناجی نجیب کا کہنا ہے کہ بعض حلقے انھیں یہ کہہ کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسیحی ہو کر ’’الاخوان المسلمون‘‘ کے لیے کام کر رہے ہیں، حالانکہ میں الاخوان المسلمون کے لیے نہیں بلکہ الاخوان المصریون کے لیے کام کر رہا ہوں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ بعض سنجیدہ مسیحی راہ نماؤں کی طرف سے شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی حمایت دراصل انسانی سوسائٹی کے لیے آسمانی تعلیمات کی ضرورت کا اظہار ہے اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے آسمانی تعلیمات کو مستند او رمکمل حالت میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس تناظر میں آج بھی کوئی مسلمان دانش ور مغرب کے فلسفہ وثقافت کے فکری دباؤ کا شکار ہو کر اسلامی نظام وقوانین کے بارے میں گومگو کے لہجے میں بات کرتا ہے تو اسے اقبالؒ کی زبان میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ:
یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا
رمضان المبارک ۔ حسنات کا گنج گراں مایہ
پروفیسر غلام رسول عدیم
اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ جس کی فضیلتوں اور برکتوں کا شمار ممکن نہیں، واحد وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجیدمیں آتا ہے اور دو مناسبتوں سے آیا ہے۔ اول یہ کہ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں نزول قرآن کا آغاز ہو ایا قرآن لوحِ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور پھر حکمتِ الٰہی اور ضرورتِ بشری اور حکمتِ خداوندی سے ۲۲؍سال اور ۷؍ ماہ اور ۱۴؍دن کے عرصے میں نجماًنجماً، آیۃً آیۃً، سورۃً سورۃً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔
شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ (البقرۃ۲:۱۸۵)
’’رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔‘‘
دوسری مناسبت یہ ہے کہ اسی مہینے میں روزوں کی فرضیت کے احکامات نازل ہوئے۔
مَن شَہِدَ مِنکُمُ الشَّہْرَ فَلْیَصُمْہُ (البقرۃ ۲: ۱۸۵)
’’تم میں سے جواس مہینہ میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے ۔‘‘
یوں ایک طرف یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے تودوسری طرف ماہ صیام ہے۔
لغوی طورپر رمضان ’’رمض‘‘ سے مشتق ہے جس کے معنی سخت گرمی اورتپش کے ہیں۔ اہلِ لغت نے اس لفظ کی اشتقاقی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے دو ممکنہ وجوہ بتائی ہیں:
۱۔جب ابتدامیں مہینوں کے وضع کیے گئے تویہ مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا ہوگا۔
۲۔ روزہ دار روزوں کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی حدت وشدت کا احساس رکھتاہے، اس لیے اسے رمضان کانام دیا گیا۔
رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت مکی زندگی میں نہیں ہوئی بلکہ ۲ ؍ہجری میں پہلی مرتبہ اہلِ اسلام پر روزے فرض کیے گئے اور صرف اسی ماہ کے روزے فرض کیے گئے ۔ یوں سفر ہجرت کے کم وبیش ڈیڑھ سال بعد روزے فرض ہوئے۔ یوں کلمہ طیبہ اورنماز کے بعد تیسرا رکن اسلام (روزہ) اس خصوصی مہینے سے گہری وابستگی رکھتا ہے اور تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ دین سے گہری محبت اور شیفتگی کا درس دیتا ہے۔
عظمتوں والے اس ماہ مبارک کی فضیلتیں قرآ ن وحدیث میں پوری شرح و بسط سے دی گئی ہیں۔ آج کی نشست میں ہم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ پیش کرتے ہیں۔یہ وہ خطبہ ہے جو آپ نے شعبان ۲ھ کے آخری دن ارشاد فرمایا۔ اس ایک خطبے سے رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور افادیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس خطبے کے راوی حضرت سلمان فارسیؓ فرماتے ہیں کہ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان ۲ھ کے آخری دن ہم سے یہ خطاب فرمایا:
’’اے لوگو! ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ خیروبرکت والی ہے۔ اللہ نے اس کے دنوں میں روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا اور اس کی راتوں میں قیام سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کرے، وہ ایساہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے، وہ ایساہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں ستر فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثوا ب جنت ہے۔ یہ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے آتشِ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اسے بھی روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، درآں حالیکہ روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ آئے گی۔
ہم نے عرض کیا۔اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم میں سے ہر کوئی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ثوا ب اللہ تعالیٰ پانی ملے ہوئے دودھ یا پانی کے گھونٹ پر بھی مرتب فرما دے گا۔ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کرکھلا دے، اسے اللہ میرے حوض سے پانی پلائے گا جس کے بعد اسے تشنگی محسوس نہ ہو گی تاآنکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
یہ وہ مہینہ ہے جس کا عشرہ اول رحمت ہی رحمت ہے، جس کا درمیانی عشرہ بخشش ہی بخشش ہے اور جس کا آخری عشرہ آگ سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اپنے غلام یا خادم یا ملازم کی ذمہ داریاں اس مہینہ میں کم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور اسے آتشِ دوز خ سے آزاد فرما دے گا۔‘‘ (کنزالعمال ، رقم حدیث: ۲۳۷۰۹)
سرکارِ رسالت پنا ہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آ پ کا یہ خطاب نقل کیا گیا ہے، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں خیر و برکت کے خزانوں اور حسنات و فضائل کے گنج ہاے گراں مایہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس حدیث میں اس مہینہ کی چار اہم صفات کا تذکرہ ہے:
۱۔شہر عظیم: عظمتوں والا مہینہ۔
۲۔ شہر مبارک: برکتوں والا مہینہ ۔
۳۔شہرصبر : ہمت و استقلال سے نیکیوں پر اور جرات و حوصلے سے گناہوں کے خلاف ڈٹے رہنے کا مہینہ۔
۴۔شہرمواساۃ: ایسا مہینہ جس میں لازم آتا ہے کہ ہم اپنے ابنائے جنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمدردی، غم گساری اور دل سوزی کے ساتھ پیش آئیں۔
خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اس پر عمل پیرا ہیں۔ اگراس آئینے میں دیکھ کر اپنے اندر کوتاہیاں پاتے ہیں تو ان کے ازالے کا ہم نے کیا سوچا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کے ذمے ہے۔
ماہ صیام کے ہدایا و عطایا
رمضان المبارک اپنی تمام ترجلوہ سامانیوں اور ضیاپاشیوں کے ساتھ جب پورے عالم اسلام کو بقعہ نور بنا دیتا ہے تو اس کے جلو میں ان برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے جن سے سال بھر کے دوسرے مہینے خالی ہیں۔ یوں کہنا چاہیے، رمضان ایک ابرنو بہار ہے جس سے ایمان کی کھیتیاں لہلہاتی ہیں، حسنِ عمل کے نہال پروان چڑھتے اور رحمت و بخشش کے اثمار شیریں جھولیوں میں آن گرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں خیر کے خزانے لٹتے اور نیکیوں کے بھنڈار بٹتے ہیں۔ رحمتیں محض بہانے تلاش کرتی ہیں۔ کبھی رحمت عالمِ انسانیت کو محیط ہوتی ہے تو کبھی گناہوں کی تپتی دھوپ میں مغفرت کے سائبان تن دیے جاتے ہیں اور کبھی گرفتار بلا کو نارِجہنم سے آزادی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں۔ اولہ رحمۃ، اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ (کنزالعمال ، رقم حدیث: ۲۳۷۰۹)
حالت صیام ہو یا حالت قیام، ہر دو کو اس زور سے تبشیری سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے کہ گزشتہ گناہوں کے دھل جانے کی نوید جانفزا دلوں کو سکون کی نعمت سے مالا مال کرتی ہے۔ نبوت کی ز بان فیض ترجمان ہے ، اعلا ن ہوتا ہے:
من صام رمضان ایماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ومن قام رمضان ایماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ (الجامع الصحیح للبخاری، رقم حدیث: ۱۷۶۸)
اس ماہ کے خصوصی ہدایا کو نگاہ میں رکھیے اور پھر اس کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ اس کی ایک ایک آن کس ندرت آمیز شرف کی آئینہ دار ہے۔
سب سے پہلا ہدیہ خود روزہ ہے۔ باقی مہینوں میں آپ روزے رکھیں تو محض نفلی عبادت ہو گی جس کی استحبابی قدر و قیمت تواپنی جگہ ہے مگر یہ عبادت ادائے فرض کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ رمضان اپنے ساتھ روزہ لاتا ہے اور روزہ جن جسمانی، طبعی، طبی، نفسیاتی، روحانی، معاشرتی فوائد و مصالح کو متضمن ہے، اسے لفظوں کے شکستہ پیمانوں سے ناپاہی نہیں جا سکتا۔ لفظ کیسے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو ں، روزے کی افادیت اور جزا کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ باقی عبادات میں ریاکاری اور نمود و نمائش کے سو پہلوؤں کا امکان ہے۔ محض روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کو ذرہ برا بر دخل نہیں تا آنکہ خود روزہ دار ہی نمود روزہ پر مصرنہ ہو۔ اس عبادت کا یہی اخلاصی پہلو ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں فرمایا گیا: الصیام لی و انا اجزی بہ (الجامع الصحیح للبخاری، رقم حدیث: ۱۷۶۱) ’’روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں‘‘۔ اگرچہ جزا تو سبھی اعمال کی وہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، مگر اپنی طرف یہ انتسابِ جزا روزہ کے دوسرے اعمال پر شرف و تخصص کا اظہار کرتا ہے۔
دوسرا تحفہ جو رمضان اپنے ساتھ لایا، وہ، وہ ضابطہ حیات ہے جس نے پوری کائنات میں ہلچل مچا دی۔ فرسودہ زندگی کے اندر سے ایک تازہ تر اور شادا ب تر زندگی نمودار ہوئی۔ دقیانوسی اور رسم و رواج کے مارے ہوئے آدمی کے اندر سے ایک پر عزم اور بالیدہ روح انسان برآمد ہوا جس نے چار دانگ عالم میں فکر ونظر اور علم و عمل کا ایک انقلاب تازہ پیدا کر دیا۔ یہ وہ نوشتہ دانش و بینش ہے اور وہ کتاب ہدایت ہے جس نے آتے ہی پوری نسل انسان کو یہ چیلنج کر دیا کہ اس جیسے کم از کم تین جملے ہی گھر لاؤ مگر اپنی فصاحت و بلاغت اور قدرت زبان و بیان کی جملہ توانائیوں کے باوجود نہ کوئی اس دور میں اس کی نظیر ومثال پیش کر سکا، نہ ہی آج تک اس تحدی کا جواب پیش کیا جا سکا ہے۔ آج بھی وہ چیلنج انھی زوردار لفظوں میں پورے تحکمانہ لہجے کے ساتھ موجود ہے جیسے چودہ سو سال پہلے تھا:
فَأتُواْ بِسُورَۃٍ مِّن مِّثْلِہِ وَادْعُواْ شُہَدَآءکُم مِّن دُونِ اللّٰہِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (البقرۃ ۲:۲۳)
زیادہ سے زیادہ جواب دیا گیا تو صرف یہ کہ لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ ہَذَا (الانفال ۸:۳۱) مگر یہ بھی خالی الفاظ تھے، ہر طرح کی معنوی معقولیت سے خالی۔ آج تک جواب کا انتظار ہے بلکہ قیامت تک رہے گا، جواب یقیناًنہیں بن پڑے گا۔ اس کتاب حکیم نے دلوں کے زاویے بدل دیے، نگاہوں کی آرزوئیں بدل دیں، دلبری اور دل ربائی کے طور بدل دیے، روحوں میں بے تابیاں بھر دیں اور فکر وعمل کو نئی وسعتیں عطا کر دیں۔ جس نے یہ کلام سنا اس کی تاثیر کا گھائل ہو کے رہا۔
مخدرات سرا پردہ ہائے قرآنی
چہ دلبر ند کہ دل می برند پنہانی
جس جان میں اتر گیا، اس میں زبردست انقلابی داعیے ابھارے، بالکل کائنات ہی بدل کر رکھ دی :
چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود
جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود
تیسرا ارمغان ثمین اس ماہ مبارک میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف اصل میں دنیوی آلائشوں اور بہت حد تک مکروہات زمانہ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اپنے خالق و مالک کے ساتھ تخلیے کا دوسرا نام ہے۔تخلیہ طالب ومطلوب کے راز ونیاز کا بہترین ذریعہ ہوتاہے۔ ایک عابد شب زندہ دار اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں اس زاویہ عزلت میں چپکے چپکے خضوع وخشوع کے ساتھ لو لگاتا ہے۔ کبھی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے تو کبھی اپنی تردامنی پر سسک سسک کر، بلک بلک کر معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ اس حال میں اس کی یہ دعائیں درِ اجابت سے ٹکراتی اور بارگاہِ حق میں شرف باریابی پاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات کے محسنِ اعظم نے ہر ماہ رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف فرمایا۔ ۸ھ کو فتح مکہ میں مصروفیت کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال ۹ھ میں بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ رمضان ہی ہے جس میں بنی نوع انسان کے لیے رحمتوں کے خزانے لٹتے اور انعاماتِ الٰہیہ کی بے طرح بارش ہوتی ہے۔
رحمت حق بہانہ می جوید
رحمت حق بہانمی جوید
چوتھی عطائے رمضان المبارک لیلۃ القدر ہے۔ کس حتمی انداز سے کہہ دیا گیا ہے کہ ’’لَیْْلَۃُ الْقَدْرِ خَیْْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَہْرٍ‘‘ (القدر ۹۷:۳) حساب لگائیے تو ۸۳ ؍سال ۴ ؍ماہ بنتے ہیں۔ ایک شخص بغیر کوئی دوسرا کام کیے بارگاہ ایزدی میں سرنہوڑائے، پورے استغراق و انہماک اور جذب و انجذاب کے ساتھ عبادت میں ۸۳ ؍سال ۴ ؍ماہ تک مسلسل کھڑا رہے تو بھی اس رات کی بیداری اور تعلق باللہ اس عرصہ دراز سے بھی بہتر ہے ۔ خَیْْرٌ کا لفظ تفضیل کل سے بھی کوئی اوپر درجہ ہو تو اس کو بھی شامل ہے۔ امت محمدیہ کی کوتہ عمری کا اس کثرت ثواب اور جزائے جزیل سے ازالہ کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھئے کہ تھوڑا کرنے پر بہت زیادہ انعامات کا مستحق قرار دینا اسی ذات ستودہ صفات کا شیوہ ہے جس نے اپنے آ پ کور ب العالمین اور رحمن و رحیم کے دلنواز القاب دیے ہیں۔
پانچواں عطیہ جو اس مقدس ماہ کا خاصہ ہے، وہ عیدالفطر ہے۔ اگرچہ یہ روز سعید شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے مگر یہ ہے حاصلِ رمضان ہی۔ یہ فضیلتوں والا دن ہے جس روز پورا عالم اسلام ایک ماہ کی پوری بدنی و روحانی ریاضتوں کے بعد انبساط ومسرت کے جذ بات میں ڈوب جاتا ہے۔ دل والے
بنتی نہیں ہے بادہ وساغر کہے بغیر
کے لہجے میں اس دن کی خوشیوں کو دوبالا کرتے، استعاروں سے کام لیتے ہوئے، مجاز کے پردے میں معارف کا ذکر ایسے ایسے حسین پیرا یہ میں کرتے ہیں کہ ذوق جھوم جھوم اٹھتا ہے۔
ساقیا عید ہے لا بادے سے مینابھر کے کہ مے آشام پیاسے ہیں مہینہ بھرکے
یہ ارمغان بہجت مسرتوں و شادمانیوں کا پیغام لاتا ہے۔ قربتوں اور محبتوں میں اضافے کا موجب ہے۔ روزے نے جن بہیمی قوتو ں کو مضمحل کر دیا تھا، یہ ان پر اترانے کا دن ہے۔ روح کی بالیدگی کا دن ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غرہ شوال کو دیکھتے ہی روحیں یوں مچلنے لگتی ہیں گویا کوئی سالوں کا محروم حجِ اکبر کی سعادت سے بہرہ ور ہو رہا ہو۔
روزے داراں نوں عید دا چن چڑھیا
جویں حاجیاں حج تیاریاں نیں
کیا فائدہ ہے ترکِ غذائے حلال سے
روزہ اردو اور فارسی میں ترجمہ ہے صوم کا اور صوم کے لغوی معنی ہیں باز رہنا، رک جانا، خواہ کھانے سے ہو یا کلام کرنے سے یا چلنے سے:
الصوم فی الاصل: الامساک عن الفعل مطعماًکان اوکلاماً اومشیاً (المفردات فی غریب القرآن للاصفہانی، ص۲۹۳)
’’روزہ اصل میں کسی کام سے رک جانے کانام ہے، وہ کھانا ہو بات ہو یا چلنا ہو ۔‘‘
الصوم فی اللغۃ :الامساک عن ما تناز ع الیہ النفس (تفسیربیضاوی،۲؍۴۳۵)
’’روزہ لغت میں اس چیزسے رک جانے کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس زور کر کے جائے‘‘۔
معلوم ہوا کہ روزہ نفس کی مرغوبات سے پرہیز کا دوسرا نام ہے۔ شرعی اصطلاح میں روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ بعض حلال چیزوں سے بچے رہنے کا نام ہے جن میں کھانا پینا اور جنسی عمل سرفہر ست ہیں۔ دیگر منکرات عام زندگی میں بھی قابل پرہیز ہیں، بحالت روزہ توبدرجہ اولیٰ ممنوع ہوں گے۔
کھاناپینا زندگی کی بدیہی ضروریات میں سے ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کھانا پینا ہی زندگی کی غایت ہے؟ اس کا جواب انسانی فکر نے د و طرح دیا ہے:
۱۔زیستن برائے خوردن، کھانے ہی کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔
۲۔خوردن برائے زیستن، ز ندگی گزارنے کے لیے کھانا چاہیے۔
پہلا طرزِ فکر وہ ہے جو مادہ پرستانہ نظریات نے دیا ہے۔ اس نقطہ نگاہ کے مطابق تن پروری ہی انسانی زندگی کی غایت اولیٰ ہے ۔ ایسے افراد یا ایسے معاشرے اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے پیٹ پوجا سے آگے کوئی حقیقت نہیں دیکھ سکے۔ان کا نعرہ مستانہ یہی ہوتا ہے:
بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست
Eat, drink and be merry, for tomorrow you will die.
یہ زندگی کو دیکھنے کا اپیقورین (Epicurean) مطمح نظر ہے۔
دوسرا نقطہ نگاہ وہ ہے جس کے پیچھے وحی کی قوت محرکہ اور الہامی سوچ کے دھارے بہہ رہے ہیں۔ کھانا ایک ناگزیر ضرورت حیات ہے، مگر محض کھانا اور شکم پروری ہی غایت حیات نہیں۔ یہ پیغمبرانہ طرزِفکر ہے۔ اس سوچ کے مطا بق جسم کا جان سے رشتہ قائم رکھنا از حد ضروری ہے، مگروہ تن پروری جو تن آسانی پیدا کر دے، مطلوب نہیں۔ یہاں جاں پروری اور روح کی پرورش و تربیت کے وسائل کو بروئے کار لانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔
اسلام دین فطرت ہے اور انسانی فطرت کی نشوونما کے جملہ اسباب فراہم کرتا ہے۔ وہ کھانے پینے میں اِسراف کو فسق سے تعبیر کرتا ہے تو اس سے کلیۃً بچے رہنے کو رہبانیت جانتا ہے۔ یوں وہ ’’خیر الامور اوسطہا‘‘ کا معیار پیش کر کے ہر طرح کی انتہاپسندی کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے، لہٰذا روح انسانی کی، جو ایک لطیف چیز ہے، نشوونما کے لیے اس نے سال بھر میں ایک ماہ کا ایسا ریفریشر کورس دیا ہے جس سے روح کی کثافتیں دھلتی اور اس میں لطافتیں در آتی ہیں۔ یہی مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآ ن کہتا ہے:
شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ (البقرۃ ۲:۱۸۵)
’’رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ‘‘۔
اور فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی توثیق یوں کی گئی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ( یکے از عشرہ مبشرہ ) نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی:
یا رسول اللّٰہ ! اَخبِرنِی عما فرض اللّّٰہ عَلَیَّ من الصیام؟ قال: شہر رمضان ( الجامع الصحیح للبخاری، رقم حدیث: ۱۷۵۸)
’’اللہ کے رسول! مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر کون سے روزے فرض کیے ہیں ؟ فرمایا: رمضا ن کا مہینہ ‘‘۔
روحانی لطافتوں میں اضافے کے لیے روزہ بہترین تد بیر ہے۔ یوں سمجھئے کہ جسم وجان کے کئی امراض کے لیے یہ ایک پرہیز ہے، جس طرح نماز جسم وجا ں کی صحت وبقا کے لیے دوا ہے۔ دوا اور پرہیز دونوں کی اہمیت سے کسی بھی دور میں کسی بھی صاحبِ فہم کو کبھی انکار نہیں رہا، بلکہ بعض نے پرہیز کی افادیت کے پیش نظر یہ تک بھی کہہ دیاہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس پرہیز سے نہ تو بھوک پیاس کی شدت اور تکلیف مالایطاق مقصود ہے اور نہ ہی اذیت رسانی، بلکہ واضح طور پر اس کی غایت بتا دی گئی ہے اور وہ ہے لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقو یٰ شعار ہو جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دراصل اس احساس کا نام ہے جس سے انسان کے دل میں نیکی کی طرف شدید رغبت ہوتی ہے اور گناہوں سے سخت نفرت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دراصل اسی غایت اولیٰ کے لیے فرض کیا گیا ۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو گیا تو روزہ، روزہ ہے، ورنہ بھوکا پیاسا رہنا نہ مفید مطلب ہے، نہ مقصود و مطلوب ہے۔ اس حقیقت سے سرکارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان واجب الاذعا ن سے یوں پردہ اٹھایا ہے:
رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع (سنن ابن ماجہ، رقم حدیث: ۱۶۸۰)
’’کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔‘‘
وہ شخص بڑا ہی محروم القسمت ہے جو بھوکا پیاسا رہ کر اور اپنے آپ کو نڈھال کر کے بھی مفسدات روزہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور تقویٰ شعاری سے محروم رہتا ہے۔ جب حرام کھانے سے اجتناب نہ کیا جائے تو حلال کھانا ترک کر دینے سے کیا فائدہ!
کیا فائدہ ہے ترکِ غذائے حلال سے
روز ے میں جب نہ عزم ہو ترکِ حرام کا
قرآن مجید بطور کتاب تذکیر ۔ چند توجہ طلب پہلو
محمد عمار خان ناصر
(الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں دورۂ تفسیر قرآن کے شرکا سے گفتگو۔)
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد!
قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اس کے تفسیری مباحث پر غور کرتے ہوئے ایک بنیادی سوال جس کے حوالے سے قرآن مجید کے طالب علم کا ذہن واضح ہونا چاہیے، یہ ہے کہ قرآن کا اصل موضوع اور قرآن نے جو کچھ اپنی آیات میں ارشاد فرمایا ہے، اس سے اصل مقصود کیا ہے؟
اس سوال کا جواب ہمیں خود قرآن مجید کی تصریحات سے یہ ملتا ہے کہ یہ اصل میں کتاب تذکیر ہے۔ قرآن نے اپنے لیے ’ذکر‘، ’تذکرہ‘ اور ’ذکری‘ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی کرانا۔ ایسے حقائق جو انسان کے علم میں تو ہیں اور وہ ان سے بالکل نامانوس نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ان سے غفلت کا شکار ہو گیا ہے اور وہ اس کے فعال حافظے سے محو ہو گئے ہیں، وہ حقائق اسے یاد کرانا، ان کی طرف اس کی توجہ مبذول کرنا اور ان حقائق کی یاد دہانی سے اس کو اپنی زندگی میں ایک خاص طرح کا رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کرنا، یہ ’تذکیر‘ کی اصل روح ہے۔ معروف اور مانوس لیکن بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرانا اور ا س یادد ہانی کے ذریعے سے انسان کے فکر کو ، اس کے عمل کو اور اس کے رویے کو ایک خاص رخ پر ڈالنا، یہ تذکیر ہے۔
قرآن مجید اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے ایک کتاب تذکیر ہے۔ اللہ تعالیٰ چند حقائق کی تذکیر انسان کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حقائق انسان کے ذہن میں مستحضر رہیں اور انسان کا دھیان اور اس کی توجہ ان پر لگی رہے اور ان کی مدد سے وہ زندگی کے ایک ایک قدم پر صحیح راستے پر قائم رہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے لیے جو قانون، ضابطے، قاعدے، سنن اور نوامیس مقرر کیے ہیں جن کے تحت وہ اس دنیاکا نظام چلا رہا ہے، خاص طو ر پر انسانوں کے معاملات وہ جن ضابطوں کے تحت چلاتا ہے، ان کا تعارف انسان کو کروانا، یہ نزول قرآن کی اصل غایت ہے۔
قرآن مجید کے جتنے مضامین ہے، ان کی آپ ذیلی تقسیمات کریں تو وہ بے شمار بن جاتے ہیں او رمختلف اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے قرآن میں پھیلے ہوئے مضامین ومطالب کو مختلف عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک معروف تقسیم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب ’الفوز الکبیر‘ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
۱۔ تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت وربوبیت کی جو نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، ان کی یاد دہانی۔
۲۔ تذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دنیا کی مختلف قوموں کے ساتھ نعمت ونقمت، دونوں پہلووں سے جو معاملہ کیا ہے، ان کی یاد دہانی۔
۳۔ تذکیر بما بعد الموت، یعنی اس بات کی یاد دہانی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جو ایک یوم الجزاء آنے والا ہے، اس دن اللہ تبارک وتعالیٰ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔
۴۔ احکام وشرائع، یعنی شریعت کے وہ قوانین جن کی پابندی اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے مطلوب ہے۔
۵۔ علم المخاصمۃ، یعنی قرآن کا مخاطب بننے والے جو گروہ قرآن کے دعاوی اور اس کے پیغام کو تسلیم کرنے اور اس کی دعوت کو قبول کرنے سے گریزاں تھے اور اس پر ان کے ذہن میں کچھ استدلالات اور کچھ شبہات تھے، ان کا جواب دینا اور ان کی تردید کر کے صحیح بات کو واضح کرنا۔
یہ بڑی حد تک ایک جامع تقسیم ہے جس میں قرآن مجید کے کم وبیش سارے نمایاں مطالب اور مضامین آ جاتے ہیں۔ اب ان پانچوں پر اگر آپ غور کریں تو مرکزی نکتہ یہ نکلے گا کہ انسان کو اس بات کی پہچان کرا دی جائے کہ اس کائنات کا خالق ومالک کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی صفات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اور جو مظاہر وجود میں آتے ہیں، وہ کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے وہ کون کون سے قوانین مقرر کیے ہیں جن کے تحت وہ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ گویا یہ سب مضامین مختلف پہلووں سے تذکیر ہی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں اور مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے انسان کے ذہن میں اس بات کے شعور کو راسخ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کے ذہن میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا صحیح تصور قائم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کسی بھی ہستی کے بارے میں جو تصور ہوگا، اسی کے لحاظ سے اس کا اس کے ساتھ تعلق بھی قائم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ، اس کی صفات اور اس کے قوانین اور اس کے معاملہ کرنے کے اصولوں اور ضوابط کا جو تصور انسان کے ذہن میں ہوگا، اسی کے لحاظ سے انسان کا تعلق بھی خدا کے ساتھ قائم ہوگا۔ یہ ساری باتیں جس درجے میں انسان کے ذہن میں واضح ہوں گی، اسی کے لحاظ سے خدا کے ساتھ اس کا تعلق بھی ایک خاص رنگ اختیار کر لے گا۔
اللہ نے اپنے لیے کچھ نوامیس مقرر کیے ہیں جن کے تحت وہ اپنی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کوئی دوسری ہستی اللہ کو کسی بات کی پابند نہیں کر سکتی: لَا یُسْئلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَہُمْ یُسْأَلُونَ (الانبیاء: ۲۳) ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عالی صفات مثلاً عدل، رافت ورحمت کے تقاضے سے خود اپنے لیے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں جن کی پابندی وہ کہتا ہے کہ میرے ذمے لازم ہے۔ کسی دوسرے نے لازم نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن ان کی پابندی اس نے خود اپنے ذمے لازم کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ: حَقّاً عَلَیْْنَا (یونس: ۱۰۳)۔ یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اس کی پابندی اب ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو قوانین او ر نوامیس مقرر کیے ہیں، ان کے لیے قرآن نے ’سنت‘ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مثلاً دنیا میں حق کا انکار کرنے والی قوموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قانون بنایا ہے جس کے ظہور کی مثالیں تاریخ میں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہیں۔ قرآن اس کو ’سنت اللہ‘ کہتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا: سُنَّۃَ اللَّہِ فِیْ الَّذِیْنَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّۃِ اللَّہِ تَبْدِیْلاً (الاحزاب: ۶۲)۔
اللہ نے اس ساری کائنات کے لیے کیا ضابطے بنا رکھے ہیں، وہ تو اس نے ہمیں نہیں بتائے۔ ہمیں تو ا س نے قرآن میں مخاطب کیا ہے اور صرف اس دائرے کے قوانین اور ضابطے بتائے ہیں جس کا تعلق ہم انسانوں سے ہے۔ سورج چاند اور دوسری مخلوقات کو اس نے کن قوانین کے تحت بنایا ہے، وہ اس نے ہمیں نہیں بتائے۔ کائنات کے مادی قوانین بھی، جن کو سائنس دریافت کرتی ہے، قرآن کا موضوع نہیں کہ وہ انسان کو یہ بتائے کہ سورج، چاند اور دوسرے مظاہر فطرت کن قوانین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی مخلوقات سے متعلق جو اخلاقی قوانین ہیں، ان کی وضاحت بھی قرآن کا موضوع نہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا خواہش کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے انسان کی جان لے، لیکن آپ جانوروں میں دیکھیں گے کہ بہت سے درندوں کی زندگی ا ور بقا کا دار ومدار ہی اس پر ہے کہ وہ کسی دوسرے جاندار کی، بسا اوقات اپنے ہی کسی ہم جنس جاندار کی جان لیں اور ا س کے گوشت سے اپنا پیٹ بھریں۔ اب حیوانات کے اور اسی طرح دوسری بے شمار مخلوقات کے معاملات کن اخلاقی قوانین اور ضابطوں پر مبنی ہیں، ان کی وضاحت قرآن کا موضوع نہیں اور نہ اس نے ان کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کا موضوع یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ نے ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے اور اس کی نقل وحرکت کا اور زندگی کی سرگرمیوں کا ایک محدود دائرہ ہے۔ اللہ نے کائنات کے اربویں کھربویں بلکہ اس سے بھی حقیر ایک چھوٹے سے حصے میں انسان کو بسایا ہے اور اس کو ایک نہایت محدود دائرے میں اختیار دیا ہے۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آزمایش کی جائے۔ اس آزمایش میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو اپنے خالق ومالک اور اس کے مقرر کردہ قوانین کی پہچان کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ صحیح طو رپر تعلق قائم کر سکے اور اس معرفت صحیحہ کا ظہور اس کے فکر وعمل اور اس کے کردار میں بھی ہو۔ یہ سب باتیں انسان کے علم میں ہونی چاہییں تاکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خدا کے حضور میں پیش ہو تو اس کی ابدی نعمتوں کا حق دار بن سکے۔
یہ ہے قرآن کی ساری تذکیر اور اس کے تمام تر مطالب ومضامین کا محور۔ دین کے جو تین بنیادی عقیدے ہیں جن پر پورے دین کی بنیاد ہے، وہ بھی یہی ہیں۔ خدا کو ماننا اس کی تمام صفات کے ساتھ اور ان تمام قوانین ونوامیس کے ساتھ جو اس نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں، نبوت ورسالت کے اس سلسلے پر ایمان رکھنا جو اللہ نے اپنی صفات اور اپنے قوانین اورضابطوں سے انسانوں کو متعارف کرانے کے لیے دنیا میں جاری کیا اور اس حقیقت پر ایمان رکھنا کہ دنیا کی اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی بھی آنی ہے جس میں انسان اپنے قول وعمل کے لحاظ سے ابدی عذاب یا ابدی نعمتوں کا مستحق قرار پائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کا ایک اور نہایت اہم پہلو بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید سے اس کا یہ مطمح نظر بڑے غیر مبہم طریقے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے لوگ اسی چیز کے حصول پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں جو اس کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی اپنی دلچسپیاں لے کر آئیں اور ان میں الجھ کر رہ جائیں۔ قرآن نے بعض پہلووں سے اپنا یہ مطمح نظر واضح کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے اور اپنے انداز سے، اپنے اسلوب سے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے آؤ تو کیا ذہن لے کر آؤ اور تمھاری دلچسپی کا مرکزی نکتہ کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طو رپر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ واقعات پر مشتمل ہے۔ شاید ایک تہائی یا اس سے زیادہ آپ کو قرآن میں واقعات ہی ملیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اسی لیے اس حصے کو تذکیر بایام اللہ کا ایک مستقل عنوان دے دیا ہے۔ قرآن میں انبیا کے، دنیا کی قوموں کے اور قوموں کی تاریخ کے واقعات ہیں۔ ان واقعات کے ذکر سے قرآن کا مقصود انسان کا دل بہلانا یا اس کی تفریح طبع نہیں۔ گزشتہ زمانے کے واقعات کے بارے میں جستجو اور ان میں دلچسپی محسوس کرنا انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ عام طو رپر انسان جب ایسے واقعات کو سنتے ہیں تو اس کا مقصد جستجو کے جذبے کی تسکین یا محض تفریح طبع ہوتا ہے۔ تاہم قرآن کے، واقعات بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس سے اس کا مقصد وہی تذکیر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان واقعات سے انسان روحانی واخلاقی سبق حاصل کرے اور ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کے جن ضابطوں اور قوانین کا ظہور ہوا، ان کی طرف متوجہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی واقعے سے متعلق ایسا لوازمہ جو اس میں کہانی کا مزہ پیدا کرتا ہے اور ایسے پہلو جو اسے تفریح طبع کا سامان بنا سکتے ہیں، قرآن کم وبیش ہر جگہ ایسے عناصر کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ ایک طویل عرصے کو محیط سلسلہ واقعات کے بے شمار اجزا کو حذف کر کے اس کے صرف ان اجزا کو بیان کر دیتا ہے جو اس کے مقصد کے لحاظ سے مفید ہیں۔ کئی سالوں پر پھیلے ہوئے سلسلہ واقعات کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ، کچھ درمیانی حصے اور کچھ اختتامی حصہ معرض بیان میں آ جاتا ہے اور یہ تمام اجزا وہ ہوتے ہیں جو تذکیر کے پہلو سے مفید اور برمحل ہوتے ہیں۔ باقی تمام تفصیلات جن کو اگر قرآن بیان کرنے لگ جائے تو لوگ قصے میں الجھ کر رہ جائیں اور اس سے کہانی کا لطف اٹھانے لگیں، ان سب کو قرآن حذف کر دیتا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے:
قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کی پیدایش سے لے کر وادئ تیہ تک ان کی زندگی کا سفر بیان کیا ہے، لیکن اس سارے واقعے کے صرف وہ اجزا منتخب کیے ہیں جن میں تذکیر کا کوئی نہ کوئی پہلو پایا جاتا ہے اور جس سے اللہ تبارک وتعالیٰ کا کوئی خاص ضابطہ اور کوئی مخصوص قانون واضح کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیدایش سے پہلے مصر میں صورت حال کیا تھی اور بنی اسرائیل کس طرح ظلم وستم کا شکار تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کی پیدایش کا ذکر ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انھیں فرعون کی قتل اولاد کی اسکیم سے معجزانہ طو رپر محفوظ رکھا اور خود فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد اگلا منظر جو سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس درمیانی عرصے میں بھی کئی واقعات رونما ہوئے ہوں گے جن سے قرآن نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ جوانی کے زمانے کا بھی صرف وہ واقعہ منتخب کیا ہے جو سلسلہ واقعات کو آگے بڑھانے والا ہے، چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے مقابلے میں اپنے اسرائیلی بھائی کی مدد کی اور اس کے نتیجے میں انھیں ہجرت کر کے مدین جانا پڑا۔ پھر وہاں اللہ نے ان کے لیے کیا بندوبست کیا، اس کا ذکر ہوا ہے۔ مدین سے واپسی پر راستے میں انھیں نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اور پھر وہ سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کئی سالوں پر پھیلے ہوئے سلسلہ واقعات کو قرآن نے صرف چند اجزا میں سمیٹ دیا ہے۔
اس ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک خاص پہلو سے توجہ طلب ہے۔ اس واقعے کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور اگرچہ یہاں بھی قرآن نے واقعے کے وہی حصے منتخب کیے ہیں جن سے کوئی نہ کوئی تذکیری فائدہ حاصل ہوتا ہے، تاہم یہ واقعہ نسبتاً زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ حضرت یوسف کی کہانی سے متعلق بعض ایسے اہم سوالات سامنے آتے ہیں جن سے قرآن کوئی تعرض نہیں کرتا، جبکہ کہانی کے تسلسل کے اعتبار سے اس میں ایک خلا سا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان اپنے ذہنی قیاسات سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن قرآن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مثلاً یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی خواب کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص رحمت اور عنایت ہوگی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ ان کے سوتیلے بھائی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ پھر جب بھائی ان کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تم یہ سب کچھ اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن سے یہ واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن، اپنا خاندان اور یہ سارا سلسلہ واقعات اچھی طرح یاد ہے۔ انھیں معلوم ہے کہ ان کے والد کون ہیں، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، لیکن مصر میں فروخت ہونے سے لے کر منصب اقتدار پر فائز ہونے تک کے اس سارے عرصے میں وہ کہیں بھی اس بات کی کوشش کرتے نظر نہیں آتے کہ اپنے والد سے رابطہ کریں۔ ان کے والد ان کی جدائی کے غم میں نڈھال ہیں، رو رو کر بینائی کھو چکے ہیں، ان کی ملاقات کے شوق میں تڑپ رہے ہیں اور کوئی ظاہری امید نہ ہونے کے باوجود پرامید ہیں کہ یوسف زندہ ہے، لیکن ادھر حضرت یوسف کے ہاں ایسی کسی تڑپ یا کسی کوشش کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ یہ چیز عام انسانی نفسیات کے لحاظ سے بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ معلوم نہیں، حضرت یوسف نے اس سلسلے میں کیا کیا ہوگا۔ کچھ کیا بھی ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک سامنے کا سوال ہے جو شاید ہر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ جب یوسف کو اپنے والد کے بارے میں معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ان کی جدائی پر سخت بے چین اور مضطرب ہوں گے تو وہ ان سے رابطہ کر کے انھیں صورت حال سے آگاہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ خاص طو رپر بادشاہ کا وزیر بن جانے کے بعد تو کوئی ظاہری رکاوٹ بھی اس میں دکھائی نہیں دیتی، تاہم قرآن اس پہلو سے سرے سے کوئی تعرض نہیں کرتا کہ انھوں نے اس کی کوشش کی یا نہیں کی۔ نہیں کی تو کیوں نہیں کی اور اگر کی تو اس کا کیا بنا اور وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی۔
اب دیکھیں، قرآن یہاں اپنے انداز سے یہ واضح کر رہا ہے کہ جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے تو واقعے سے متعلق ایک بڑے نمایاں سوال کا جواب دینے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قاری کو اس کا جواب ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا تو نہ ملے۔ قرآن کا مقصد کہانی سنانا اور کہانی کا پورا لوازمہ فراہم کرنا نہیں۔ وہ تو حضرت یوسف کے واقعے میں تذکیر کے اور تربیت کے جو پہلو ہیں، بس ان کو سامنے لانا چاہتا ہے۔
اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ سورۂ سبا میں نہایت اختصار سے بیان ہوا ہے، وہ بھی بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے۔ بیان ہوا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ جنات جنھیں ان کی غلامی میں دیا گیا تھا، ان کو پتہ نہ چل سکا۔ زمین کے کیڑے نے حضرت سلیمان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا اور جنات کو اس وقت خبر ہوئی جب لکڑی اتنی کھوکھلی ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا وزن نہ سہار سکی اور وہ گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہاں دیکھیں، قرآن نے اپنے مقصد کے تحت واقعے کا صرف یہ پہلو بیان کر دیا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو حضرت سلیمان کی وفات کے بعد وہ اس ’’عذاب مہین‘‘ میں مبتلا نہ رہتے، لیکن اس مختصر بیان سے ایک سوال ہر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان وفات کے بعد لکڑی کے سہارے آخر کتنا عرصہ کھڑے رہے؟ ظاہر ہے کہ کیڑے کو لکڑی کو کھوکھلا کرتے ہوئے کچھ دن تو لگے ہوں گے۔ کیا اس سارے عرصے میں حضرت سلیمان وہیں لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور ان کی اس کیفیت پر کسی کو تعجب نہیں ہوا؟ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اتنے دن سے وہ نہ کہیں آ جا رہے ہیں، نہ کھا پی رہے ہیں اور نہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس سوال سے قرآن کوئی تعرض نہیں کرتا۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعے کے بیان میں بھی یہی اسلوب ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو یہودی اور مسیحی صدیوں سے یہ عقیدہ رکھتے چلے آ رہے تھے کہ حضرت مسیح کو یہودیوں نے سولی چڑھا کر قتل کر دیا تھا۔ قرآن آ کر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ یہودی نہ انھیں سولی چڑھانے میں کامیاب ہوئے اور نہ کسی اور طریقے سے قتل کرنے میں، بلکہ اس معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا جس کی وجہ سے وہ یہی سمجھتے رہے کہ انھوں نے سیدنا مسیح کو سولی چڑھا دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ نے حضرت مسیح کو بحفاظت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب دیکھیں، قرآن مذہبی تاریخ کے ایک نہایت اہم واقعے کی اصل حقیقت کو واضح کرتے ہوئے صرف دو لفظوں میں یہ کہہ کر گزر جاتا ہے کہ یہ معاملہ یہود ونصاریٰ کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ وہ اس اشتباہ کی نوعیت اور واقعے کی عملی تفصیلات سے جن سے اس پہلو پر روشنی پڑتی ہو، بالکل کوئی تعرض نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ سب باتیں اس کے مقصد سے متعلق نہیں۔ آپ غور کرتے رہیں، چاہیں تو اسرائیلیات کو پڑھیں اور یہود ونصاریٰ کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔
حاصل یہ ہے کہ کہ واقعات کے بیان میں قرآن جگہ جگہ اپنے اسلوب سے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جتنی بات اس نے بیان کی ہے، یقیناًاس کی کچھ زائد تفصیلات بھی ہیں جن کو جاننے کی انسان کو جستجو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کو ان سے غرض نہیں۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پورے واقعے کو اس کی جملہ تفصیلات کے ساتھ بیان کرے تاکہ سننے والے کو کسی پہلو سے تشنگی کا احساس نہ ہو۔ وہ قاری کی توجہ کو اپنی نظر میں مقصود معنوی حقائق پر مرکوز رکھنا چاہتا ہے اور اپنے انداز سے قاری کو متنبہ کرتا رہتا ہے کہ واقعات کے بیان سے قرآن کے اصل مقصد کو سمجھے اور اسی کو اپنا مطمح نظر بنائے۔
قرآن کے اصل مقصد کی وضاحت کے ضمن میں، میں نے جو کسی قدر طول بیانی سے کام لیا، شاید وہ آپ کو بے فائدہ دکھائی دیتی ہو۔ اس لیے کہ یہ بات بظاہر ایک سادہ سی اور معلوم ومعروف سی بات لگتی ہے اور ظاہری نظر سے دیکھیں تو علم تفسیر کے طلبہ کے سامنے اس کا ذکر شاید تحصیل حاصل بھی لگتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنا یہ تعارف کروایا ہے اور اس کے لفظ لفظ سے اس کا یہ مقصد ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اور یہ یہ اس کے مطالبات ہیں۔ اس لیے یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نکتے کو خاص طو رپر موضوع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے اور خاص طور پر علم تفسیر سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ کے لیے خاص طو رپر سمجھنے کی بات ہے۔
اصل میں ہوا یہ ہے اور انسانی تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب نے اپنا جو اصل موضوع متعین کیا اور اپنے مضامین ومطالب کا جو اصل مقصد بیان کیا، ایک خاص وقت گزر جانے کے بعد لوگوں کی توجہ اس اصل مقصود سے ہٹ کر کچھ اور باتوں پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے ’توجہ ہٹنے‘ کا لفظ استعمال کیا ہے، لاعلمی یا جہالت کا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اصل مقصد لوگوں کے دائرۂ معلومات میں نہیں رہتا۔ وہ لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، لیکن جس چیز کو ‘مرکز توجہ‘ کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ اس کتاب کو اتارنے سے جو چیز اللہ کو مقصود ہے کہ انسان جب اس کو پڑھیں تو ان کے ذہن کا رخ اس طرف ہو، وہ مرکز توجہ نہیں رہتی اور اس کے ساتھ ملحق، اس کے ارد گرد گھومنے والی کچھ دوسری باتیں، کچھ اضافی معلومات اور کچھ زوائد زیادہ توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کے لیے ظاہر ہے کہ دلچسپی کی چیزیں بے شمار ہیں۔ یہ چیزیں مادی بھی ہیں اور ذہنی وفکری بھی۔ ایک عام آدمی کی سوچ کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور اس کے فکر کی سطح بھی سادہ ہوتی ہے، لیکن جب علم ودانش سے دلچسپی رکھنے والے لوگ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کو دیے گئے بہت تھوڑے اور محدود علم کے باوجود، اس دنیا میں علم کے رنگ بے شمار اور اس کے اطراف وجوانب ان گنت ہیں اور علمی وفکری مزاج رکھنے والے افراد قدرتی طو رپر ان میں دلچسپی بھی محسوس کرتے ہیں۔ انسان اپنی بنیادی فطرت کے لحاظ سے علوم وفنون میں اور ان تمام چیزوں میں غیر معمولی کشش محسوس کرتا ہے جنھیں انسان اپنی عقل سے دریافت کر سکتا ہے۔
اب جب اس طرح کے مختلف علوم وفنون کا پس منظر رکھنے والے حضرات کلام الٰہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر انسان میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اپنے ذوق پر جس چیز کا غلبہ ہے، وہ کتاب الٰہی کو بھی اسی رنگ میں دیکھے۔ اس کی توجہ کتاب الٰہی میں ان پہلووں پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے جو اس کے اپنے ذہنی وفکری پس منظر سے ہم آہنگ ہوتی ہیں اور وہ انھیں زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے غور وفکر اور اس کی دلچسپی کے دائرے سے تعلق رکھنے والے جو پہلو ہیں، انھیں زیادہ اجاگر کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، صحابہ وتابعین اور ابتدائی ایک دو صدیوں کے بعد رفتہ رفتہ قرآن مجید کی تفسیر میں کئی انداز سامنے آ گئے۔ آپ تاریخ تفسیر کی کوئی کتاب، مثلاً محمد حسین ذہبی کی مشہور کتاب ’التفسیر والمفسرون‘ اٹھا کر دیکھ لیں جس میں علم تفسیر کی تاریخ اور اس کے مختلف مناہج کا تعارف کروایا گیا ہے۔ آپ کو تفسیر کے ضمن میں بہت سے رجحانات مثلاً تفسیر بالراے، تفسیر بالروایۃ، بلاغت کے پہلو سے قرآن کی تفسیر، تصوف کے نکات ومعارف کے لحاظ سے آیات قرآنی کی تشریح، فقہی احکام کے استنباط کے پہلو سے قرآن کی تفسیر اور اس طرح کے دوسرے رجحانات کا تعارف ملے گا۔ اب آپ ان سب کا تجزیہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ مختلف رجحانات کیسے وجود میں آئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کی علم نحو اور علم بلاغت کے ساتھ ایک خاص مناسبت تھی، انھوں نے اپنے زاویہ نظر سے قرآن کو دیکھا۔ ظاہر ہے کہ قرآن عربی زبان کا ایک نہایت عالی شان شہ پارہ ادب ہے اور اسالیب زبان اور نحو وبلاغت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس میں غور وفکر کے لیے نہ ختم ہونے والا مواد اور لطائف ودقائق اخذ کرنے کی ایک وسیع جولان گاہ ہے۔ اسی طرح سے فقہا، جن کی توجہ اور غور وفکر کا محور احکام وقوانین کا استنباط ہے، قرآن کی طرف متوجہ ہوئے اور انھوں نے اس کی کوشش کی کہ قرآن کی آیات سے، دلالت کے مختلف درجات کے تحت حتی کہ لطیف اشارات تک سے جتنے زیادہ سے زیادہ فقہی احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں، وہ کیے جائیں اور قرآن کے فقہی اور قانونی پہلو کو نمایاں کیا جائے۔
اس طرح جب مختلف علمی وفکری پس منظر رکھنے والے حضرات قرآن کی طرف متوجہ ہوئے تو انھوں نے اپنی اپنی دلچسپی کے لحاظ سے قرآن کو ایک خاص رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو کام ہوا، اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح قرآن کی علمی خدمت اور اس کی شرح ووضاحت کے اتنے متنوع اور گوناگوں پہلو سامنے آ گئے، تاہم اس کے ساتھ اس کا ایک سلبی پہلو بھی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ جیسے جیسے ابتدائی دور کا تفسیری ذخیرہ دیکھتے ہوئے نیچے آتے جائیں گے، آپ کو ہر دور میں تفسیر کے مباحث میں مزید تنوع اور وسعت پیدا ہوتی نظر آئے گی۔ شروع کے دور کی تفسیریں دیکھیں تو صحابہ وتابعین کے ہاں قرآن کی کسی آیت کی تشریح میں آپ کو بہت سادہ انداز نظر آئے گا۔ کوئی لفظ مشکل ہے تو وہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ آیت کے مفہوم اور عملی مصداق کو واضح کرنے کے لیے کسی واقعے کا حوالہ دے دیں گے۔ اسی کو عام طو رپر شان نزول کہہ دیتے ہیں۔ کسی آیت کے معنی ومفہوم کے حوالے سے کوئی اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اس کو وہ حل کر دیں گے۔ یہ ایک سادہ سا انداز ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ نیچے آتے جائیں گے، یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بے شمار علوم کی بحثیں مل جائیں گی۔ شروع میں لوگ اپنے اپنے مخصوص دائرے میں قرآن کے متن سے نکات ومعارف استنباط کرتے تھے۔ نحویوں نے اپنے انداز میں فوائد جمع کیے اور فقہا نے اپنے انداز میں۔ اس کے بعد جو لوگ آئے، انھوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب مباحث کو یکجا کر دیا جائے۔ اس طرح گوناگوں اور رنگا رنگ علوم وفنون کے مباحث تفسیر کے عنوان سے جمع کیے جانے لگے۔
آپ متاخرین میں سے مثال کے طو رپر پانچویں صدی کے امام رازی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد پچھلے دور میں روح المعانی دیکھ لیں۔ آپ کو دنیا جہان کے علوم سے متعلق بحثیں ملیں گی۔ ایک آیت پر غور کرتے ہوئے اہل نحو نے کیا کیا بحثیں اٹھائیں، وہ سب آپ کو مل جائیں گی۔ فقہا نے اس کے تحت کیا کیا مسائل چھیڑے، وہ بھی آپ کو دستیاب ہوں گے۔ اہل تصوف نے اس سے کیا کیا نکات مستنبط کیے، وہ بھی آپ کی ضیافت طبع کے لیے مہیا ہوں گے۔ اب اس طرز تفسیر کا سلبی پہلو یہ ہے کہ قرآن کا مختصر سا متن علوم وفنون کے اتنے بڑے انبار کے نیچے دب کر رہ جاتا ہے۔ انسانی ذہن کی یہ محدودیت مسلمہ ہے کہ آپ اس کے سامنے بیک وقت جتنی زیادہ چیزیں رکھ دیں گے، اس کی توجہ اتنی ہی تقسیم ہوتی چلی جائے گی، جبکہ توجہ طلب چیزیں جتنی کم سے کم ہوں گی، اتنا ہی انسانی ذہن ان پر اپنی توجہ کو بہتر انداز میں مرکوز کر سکے گا۔ انسانی ذہن کی ساخت اور اس کی خصوصیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی توجہ کی مثال روشنی کی سی ہے۔ روشنی کو ایک خاص جگہ پر مرکوز کیا جائے تو جس جگہ پر روشنی براہ راست پڑ رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ واضح ہوتی ہے جبکہ اس کے اطراف وجوانب میں جو چیز اس مرکز سے جتنا دور ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی بتدریج اندھیرے کی زد میں آتی چلی جاتی ہے۔ یہی معاملہ انسانی توجہ کا ہے۔ انسان بیک وقت اپنی مکمل توجہ ایک آدھ سے زیادہ چیزوں پر مرکوز نہیں کر سکتا۔ ایک وقت میں آپ کی توجہ جس چیز پر جتنی زیادہ مرکوز ہوگی، اتنی ہی وہ آپ کے سامنے واضح ہوگی، جبکہ باقی چیزیں درجہ بدرجہ توجہ کے دائرے میں تو ہوں گی، لیکن اس طرح سے آپ کے ذہن کے سامنے واضح نہیں ہوں گی۔ چنانچہ متنوع علوم وفنون سے پیدا ہونے والی مختلف بحثوں کو تفسیر کے دائرے میں لے آنے کا بڑا نقصان یہ ہو اہے کہ قرآن کا اصل موضوع اور اس کا اصل مقصد یعنی تذکیر بالکل دب جاتا ہے۔ اب ایک طالب علم جو مختلف علوم وفنون سے واقف ہے اور ان میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ جب قرآن کی طرف آتا ہے تو اس کے اصل پیغام اور اس کے اصل فائدے کی طرف جو قرآن چاہتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو حاصل ہو، اس کا دھیان کم جاتا ہے جبکہ زوائد اور ضمنی بحثوں اور نکات کی طرف اس کی توجہ زیادہ مبذول ہو جاتی ہے۔ وہ یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی محسوس کرتا ہے کہ یہاں علم نحو کا نکتہ کیا ہے، آیت کی شان نزول کیا ہے، علم کلام کا کون سا مسئلہ اس آیت سے متعلق ہے، قرآن نے جو بات اور جو واقعہ اجمال میں بیان کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس پر قرآن کے طلبہ کو متنبہ رہنا چاہیے اور خاص طو رپر میرے اور آپ جیسے طالب علموں کے لیے یہ بات خاص طو رپر توجہ کی محتاج ہے۔
ہماری علمی روایت میں جب مختلف علوم وفنون کا تفسیر کے ساتھ امتزاج ہوا اور تفسیر کے دائرے میں یہ سب چیزیں آتی چلی گئیں اور تفسیری مواد کا حجم بڑھتا چلا گیا، تفسیر کے نام پر ہر طرح کے علوم وفنون جمع کیے جانے لگے تو لازمی طور پر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ قرآن کے طلبہ کی اور تفسیر کے عنوان سے قرآن پر غور کرنے والے لوگوں کی توجہات ان زوائد کی طرف زیادہ ہوتی گئیں اور اکابر اہل علم کو اس صورت حال پر بے اطمینانی کا اظہار کرنا پڑا۔ مثال کے طو رپر ہمارے قریب کے دور میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ’الفوز الکبیر‘ میں اس پر باقاعدہ بحث کی ہے کہ یہ جو تفسیروں میں شان نزول کی روایات کا انبار لگا ہوا ہے، اس سے قرآن کے طالب علم کو خلاصی دلوانی چاہیے، کیونکہ ان میں سے بیشتر روایات کا متن قرآن کے فہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا ایک بہت محدود حصہ ہے جس کا انسان کے علم میں ہونا قرآن کے متن کے فہم کے لیے ضروری ہے اور یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں جہاں اس نے عہد نبوی کے بعض متعین واقعات کو سامنے رکھ کر ان پر تبصرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے وہ سارا واقعہ اپنے متن میں بیان نہیں کیا۔ اس واقعے کی تفصیلات سے اس کے اولین مخاطبین پہلے سے واقف تھے۔ قرآن نے اس کو سامنے رکھ کر بس تبصرہ کر دیا ہے۔ اب اگر تاریخ وسیرت کا وہ حصہ آدمی کی نظر میں نہیں ہوگا جو ان آیات کے واقعاتی پس منظر پر روشنی ڈالتا ہے تو وہ قرآن کے تبصروں کی معنویت سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر، یہ جو ہر دوسری تیسری آیت کے تحت شان نزول کے نام سے دو چار واقعات درج کر دینے کا رجحان ہے، یہ تفسیر کے طالب علم کو ایک بے معنی مشغلے میں الجھا دینے کا ذریعہ ہے۔ وہ ساری زندگی اس طرح کی چیزیں جمع کرنے اور پڑھنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ ان چیزوں کا قرآن کے متن کے فہم سے کوئی خاص واسطہ نہیں۔
مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دوسرے مقام پر غالباً شاہ صاحب نے ہی علم تجوید سے اشتغال پر بھی اسی نوعیت کا تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متاخرین کے ہاں قرآن کے الفاظ کی ادائیگی اور تلاوت میں لمبے چوڑے قواعد کی رعایت اور پابندی کا جو اہتمام دیکھنے کو ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی ساری توجہ تلفظ کی تصحیح اور تحسین صوت پر مرکوز ہو گئی ہے اور قرآن کے اصل مقصود سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ شاہ صاحب کی اس بات میں بڑا وزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاں تو اس معاملے میں بڑی سہولت اور تیسیر دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ درخواست کی کہ قرآن تو بڑا اعلیٰ کلام ہے، بڑی فصیح وبلیغ عربی میں اترا ہے، جبکہ میری امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، سارے قرا نہیں ہیں۔ ان میں بوڑھے بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں۔ ان سب کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرآن کو اس کے بالکل معیاری لہجے پر پڑھیں۔ ان کے لیے یہ رخصت ہونی چاہیے کہ جو شخص جس طرح بآسانی قرآن کو پڑھ سکے، پڑھ لے۔ صحابہ کے ہاں آپ دیکھیں، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر وہ ایک عجمی بوڑھے کو سورۂ دخان پڑھا رہے تھے۔ اس میں طَعَامُ الْأَثِیْمِ (الدخان: ۴۴) کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ لفظ اس بوڑھے کی زبان پر نہیں چڑ ھ رہا تھا۔ عبد اللہ بن مسعود نے دو چار مرتبہ اسے کہلوانے کی کوشش کی، لیکن جب ناکامی ہوئی تو فرمایا کہ تم طعام الفاجر پڑھ لو۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اگر أَثِیْمِ زبان سے ادا نہیں ہوتا تو فاجر پڑھ لو۔
آج ہم قرآن کی تلاوت کے ایک معیاری لہجے کو کسوٹی بنا کر کہتے ہیں کہ ساری امت اسی کے مطابق پڑھے اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو لفظوں کی ادائیگی میں معمولی فرق سے کفر وایمان کے اور نماز کے ادا ہونے یا نہ ہونے کے مسئلے پیدا ہوجائیں گے۔ یہ غلو کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا انداز یہ نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کو جس حد تک انسان کے لیے ممکن ہو، تجوید کے قواعد کے مطابق تحسین صوت اور تصحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش یقیناًکرنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی محنت اور توجہ کا مرکز ہی اس چیز کو بنا دیں کہ قرآن کی تلاوت میں اصل کام تو بس اس کو تجوید کے مطابق پڑھنا ہی ہے تو یہ بات اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تجوید پر بہت زیادہ توجہ دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اسی کو مقصود سمجھ لیتے ہیں اور قرآن کے معانی ومطالب سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آدمی حسب استطاعت بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن محنت اور توجہ کا اصل مرکز یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن جن حقائق کی تذکیر کرنا چاہتا ہے، اللہ کی جن صفات کی اور اللہ کی جن سنن کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیا ہیں اور ان چیزوں کی تذکیر کی مدد سے مجھ سے کن تقاضوں کی تکمیل مطلوب ہے؟
یہاں میں اسی ضمن میں امام شاطبی کی ایک بات کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا۔ امام شاطبی آٹھویں صدی ہجری کے ایک بڑ ے نامور مالکی عالم اور فقیہ ہیں۔ ’’الموافقات فی اصول الشریعہ‘‘ کے نام سے ان کی کتاب اصول فقہ اور فلسفہ دین میں ان چند اعلیٰ درجے کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے جو اس موضوع پر علماے امت نے لکھیں۔ اس میں بے شمار مباحث ہیں۔ اس کی قسم ثالث ’کتاب المقاصد‘ کے عنوان سے ہے۔ اس میں انھوں نے ایک مستقل فصل قائم کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے اور اس کے پیغام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص اصول ہے جسے صحابہ ملحوظ رکھتے تھے۔ وہ یہ کہ جب آپ کلام اللہ کو پڑھیں تو آپ کی توجہ اس کے ’’مقصود اعظم‘‘ کی طرف ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کلام بہت سے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ایک آیت میں مثال کے طو رپر دس پندرہ الفاظ ہوں گے۔ ہر لفظ کا اپنا ایک معنی ہوگا۔ پھر لفظوں سے جب تراکیب بنتی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ مسائل وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کلام کے اجزا میں اور اس کے ایک ایک لفظ میں الجھے رہیں گے تو پورے کلام کا جو اصل نکتہ ہے جس کا متکلم ابلاغ کرنا چاہتا ہے، اس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اگر آپ کو اجزاے کلام میں سے کسی جز کا انفرادی فہم نہ حاصل ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پورے کلام کا حاصل اگر آپ تک منتقل ہو گیا ہے تو کلام کا اصل فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ شاطبی کا مقصود اس بات سے اجزاے کلام سے کماحقہ واقفیت کی اہمیت کو کم کرنا نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ پر لغت اور نحو کے اعتبار سے اگر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی تو آپ کے فہم کا درجہ اور سطح بہت بلند ہو جائے گی، تاہم قرآن کے اصل مقصد یعنی تذکیر کے پہلو سے شاطبی کا بیان کردہ یہ نکتہ بہت اہم اور مفید ہے کہ آپ کی نظر کلام کے مجموعی مفہوم پر رہنی چاہیے۔ اگر مجموعی طو رپر کلام کا مقصود آپ پر واضح ہو گیا ہے تو اجزا میں سے کسی ایک آدھ جز کا معنی معلوم نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس بات کو واضح کرنے کے لیے شاطبی نے حضرت عمر کے ایک مشہور واقعے کا حوالہ دیا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ سیدنا عمر نے ایک موقع پر سورۂ عبس کی آیت وَفَاکِہَۃً وَأَبّا (عبس: ۳۱) پڑھی اور لوگوں سے پوچھا کہ لفظ ’اب‘ کا کیا مطلب ہے؟ شاید ا س کا لغوی معنی انھیں معلوم نہیں تھا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ ’ما کلفنا ہذا‘۔ اگر نہیں پتہ تو ہمیں اس مشقت میں نہیں ڈالا گیا کہ ایک ایک لفظ کی پوری لغوی تحقیق ہمارے علم میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سوال کسی دوسرے شخص نے ان سے کیا تو انھوں نے جواب میں کہا کہ ’نہینا التکلف والتعمق‘۔ ایک لفظ کا معنی اگر ہمیں معلوم نہیں تو ہمیں خواہ مخواہ تکلف کرنے اور تعمق میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔
اب یہاں کلام کا جو اصل پیغام ہے، وہ بالکل واضح ہے۔وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۂ عبس کے اس حصے میں اپنی بہت سے نعمتوں کو گنوا کر انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات اور احسانات کیے ہیں اور ان کے اعتراف کے طو رپر تمھارا کیا فرض بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت پر نظر کرے کہ اسے کس چیز سے اور کیسے پیدا کیا گیا اور پھر یہ سوچے کہ اس جیسی حقیر اور بے حیثیت مخلوق کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں مہیا کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پانچ سات نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ان میں سے ایک لفظ کا معنی اگر کسی شخص کو معلوم نہیں تو اسے ایک ’’علمی‘‘ نقصان تو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن کلام کا مجموعی مفہوم اور اصل مقصود بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی نعمتوں کے اعتراف اور قدر دانی اور اس کے مقابلے میں اپنی ناشکری کا احساس بیدار ہو۔ اگر ان آیات کو پڑھ کر یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہو گیا ہے تو قرآن کا مقصود حاصل ہو گیا ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اصل توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر دل میں خدا کا قرب حاصل کرنے کی، خدا کی عبادت کی اور خدا کی رضا کے حصول کی تڑپ پیدا ہو۔ اس بنیادی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ جتنے چاہیں، ز وائد بھی حاصل کریں۔ آپ قرآن سے بلاغت کے نکتے بھی مستنبط کریں، نحو کے اسالیب پر بھی غور کریں، احکام وشرائع اور لطیف نکات بھی اخذ کریں، یہ سب کریں، لیکن اصل غرض کی قیمت پر نہیں۔ قرآن سے حاصل کرنے کی اصل چیز یہی تذکیر ہے۔ اگر یہ مجھے اور آپ کوحاصل نہیں ہو رہی تو باقی سب چیزیں درحقیقت ہماری توجہ کو بٹانے اور قرآن کے مقصد سے نظر ہٹانے کا کام کر رہی ہیں۔ کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ اس طرح کی باقی سب چیزوں سے کچھ عرصے کے لیے ’’ایلا‘‘ کر لیں۔ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنانے کی کوشش کریں کہ جو غذا آپ کو قرآن دینا چاہتا ہے، آپ کی طبیعت اس سے مانوس ہو جائے۔ جب یہ ہوجائے اور قرآن سے تذکیری غذا حاصل کرنے کا ذوق پختہ ہو جائے تو پھر باقی چیزیں بھی ان شاء اللہ قرآن کے طالب علم کے لیے مفید ہوں گی، لیکن اس کے بغیر یہ جو تفسیری نوعیت کی بحثیں ہیں، یہ آپ کی توجہ کو ہٹاتی رہیں گی۔ آپ کو تفسیری معلومات، نکات اور معارف تو بہت حاصل ہو جائیں گے، لیکن قرآن سے جو روحانی فائدہ آپ کو ملنا چاہیے، وہ ممکن ہے نہ ملے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ضمن میں اس حد تک اہتمام فرمایا کہ عام دعوت وتبلیغ کے لیے او رمسلمانوں کی عمومی تعلیم کے لیے نصاب صرف قرآن کو قرار دیا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اس طرح مقصوداً واہتماماً تبلیغ اور تعلیم کا موضوع نہیں بننے دیا۔ چنانچہ ایک عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ خود اپنے ارشادات واقوال بھی لکھنے کی اجازت صحابہ کو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، بلکہ ایک روایت کے مطابق لوگوں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ اسے مٹا دو۔ مقصد یہ تھا کہ قرآن ہی کو لکھا جائے، اسی کو یاد کیا جائے، اسی کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اسی کو پڑھا اور اسی کو پڑھایا جائے۔ اس میں یہ حکمت بھی یقیناًملحوظ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وفرمودات قرآن کے متن میں شامل نہ ہو جائیں، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ پڑھنے پڑھانے اور تعلیم وتبلیغ کا موضوع قرآن کے متن کے علاوہ اور کوئی چیز نہ بننے پائے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور میں باقاعدہ تعلیمی پالیسی بنائی اور مختلف علاقوں میں نئے مسلمان ہونے والوں کی تعلیم وتربیت کے لیے اساتذہ اور معلمین کی تقرری کا ایک نظام وضع کیا تو انھیں یہ ہدایات دیں کہ جب تک لوگ قرآن سے مانوس اور واقف نہ ہو جائیں، انھیں احادیث سنا کر ان کی توجہ قرآن سے ہٹا نہ دینا۔ اس طرح انھوں نے واضح کیا کہ لوگوں کو اور خاص طو رپر نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے نصاب تعلیم صرف قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ساتھ شامل ہوگی تو وہ ان کی توجہ قرآن سے ہٹا دے گی۔ ان کی توجہ صرف قرآن کی طرف رہے اور جب تک قرآن کے ساتھ ان کی واقفیت اور مناسبت گہری نہ ہو جائے اور وہ قرآن کے انداز کو سمجھنے کی صلاحیت بہم نہ پہنچا لیں، کسی اور چیز میں ان کی توجہ بٹائی نہ جائے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ، چاہے وہ دینی نوعیت رکھنے والی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی کیوں نہ ہوں، ایسا اشتغال نہیں ہونا چاہیے جو قرآن کے متن کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کو کمزور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔
قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق زندگی بھر کا تعلق ہے۔ اس تعلق کے قائم ہونے ، اس کے نشوو نما پانے اور مضبوط سے مضبوط تر ہونے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جس میں انسان یہ کہہ سکے کہ میں نے قرآن سے جو سیکھنا تھا، سیکھ لیا ہے اور اب میرے لیے اس کو پڑھنا محض تکرار ہے۔ قرآن کو روزانہ پڑھنا اور اس کے کسی نہ کسی حصے پر باقاعدہ غور کرنا، دین کے ایک طالب علم کو یہ چیز اپنے معمولات کا حصہ بنا لینی چاہیے۔ تلاوت تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، وہ دینی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دین کے ایک طالب علم کو تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی ٹکڑے پر روزانہ غور کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس غور وفکر کے دوران میں جو سوالات سامنے آئیں، ان کو باقاعدہ طالب علمانہ طریقے پر نوٹ کریں۔ جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو نوٹ کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی نکتہ واضح نہیں ہوا تو اس کے لیے تفسیروں کی مراجعت کریں۔ قرآن کے علما اور اس پر غور وفکر کرنے والے محققین سے استفادہ کریں، لیکن اس ساری تگ ودو میں اگر دلچسپی کا محور زوائد بن جائیں تو قرآن کا اصل پیغام، جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے تک پہنچے اور وہ روحانی اثر جو قرآن چاہتا ہے کہ اس کے قاری کے دل پر پڑے، خدشہ ہے کہ انسان اس سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے کوشش کر کے، تربیت کر کے اپنے اندر اس ذوق کی نشوونما کریں۔ اس کے لیے خاصی ریاضت کی ضرورت ہوگی۔جب تک آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے اور ریاضت کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنائیں گے، قرآن سے کماحقہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن سے حاصل ہونے والا اصل فائدہ عقلی اور فکری نہیں، بلکہ جذباتی، تاثراتی اور روحانی ہے۔ قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے کافی ریاضت کرنا ہوگی کہ زوائد سے صرف نظر کرتے ہوئے اصل مقصود پر توجہ دیں اور قرآن کی آیات سے وہ روحانی غذا حاصل کریں جو قرآن چاہتا ہے کہ ہمیں حاصل ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا بہتر سے بہتر فہم حاصل کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ آمین
شخصیت پرستی اور مشیخیت کے دینی و اخلاقی مفاسد
مولانا محمد عیسٰی منصوری
علماء کرام کا ایک بنیادی کام عوام کے ذوق و سوچ و فکر کی نگہداشت بھی ہے کہ دین کے کسی شعبہ میں غلو نہ پیدا ہونے پائے، دین کا ہر کام پورے توازن و اعتدال سے جاری و ساری رہے اور ملت اسلامیہ ذہنی و فکری طور پر جادۂ اعتدال سے ہٹنے نہ پائے۔ اس کی خاطر علماء کرام کو ہر دور میں بڑے حزم و احتیاط سے کام لینا پڑا۔ سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کا شجرہ بیعت رضوان کو کٹوا دینا یا حجر اسود کے سامنے اعلان فرمانا کہ : ’’تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان‘‘ اسی حزم و احتیاط کا نمونہ تھا۔
اورنگ زیب عالمگیرؒ، جنہیں عصرحاضر کے عظیم عالم و مفکر شیخ طنطاوی نے چھٹا خلیفہ راشد کہا ہے اور اقبالؒ نے ’’ترکش مارا خدنگ آخرین‘‘، وہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے انتہائی عقیدت مند تھے بلکہ بعض نے عالمگیر ؒ کو حضرت خواجہ معصوم ؒ کا مرید لکھا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے پوتوں تک سے ایسی عقیدت و تعلق تھا کہ گولکنڈہ کی فتح کے بعد وہاں کے حکمران شاہ کی بیٹیوں میں ایک کی شادی اپنے صاحبزادے سے اور دوسرے کی حضرت مجدد ؒ کے پوتے سے کرتے ہیں۔ عالمگیر کو جو کتب نہایت عزیز تھیں، ان میں ’’مکتوبات مجدد‘‘ اور ’’دیوان حافظ‘‘ شامل تھیں جو ان کے سرہانے رکھی رہتی تھیں، مگر ایک وقت میں عالمگیر ؒ نے اورنگ آباد کے حاکم کو فرمان لکھ بھیجا کہ ان دونوں کتب کے پڑھنے پڑھانے سے لوگوں کو حکماً روک دیا جائے کہ ان کے بعض مضامین عوام کی سطح سے بالاتر ہیں۔
’’ارواح ثلاثہ ‘‘ میں حضرت گنگوہی ؒ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے:
’’حکایت: (۲۹۷) خاں صاحب قبلہ نے فرمایا کہ : ایک مرتبہ حضرت گنگوہیؒ دیوبند سے واپسی میں سہارنپور سے رامپور تشریف لے جارہے تھے ( اور غالباً حضرت پھر دیوبند نہیں تشریف لے جا سکے)۔ اگلی گاڑی میں حضرت مولانا اور حکیم ضیاء الدین صاحب تھے اور پچھلی گاڑی میں، میں اورمولوی مسعود احمد صاحب۔ حضرت نے گاڑی کے پیچھے کا پردہ اٹھا کر مجھ سے باتیں کرنی چاہیں، مگر چونکہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے بات چیت مشکل تھی، اس لیے میں گاڑی سے اتر کر اور حضرت کی گاڑی کا ڈنڈا پکڑ کر ساتھ ساتھ ہو لیا۔ حضرت نے فرمایا: ’’میاں امیر شاہ خاں! ابتدا سے اور اس وقت تک جس قدر ضرر دین کو صوفیہ سے پہنچا ہے، اتنا کسی اور فرقہ سے نہیں پہنچا۔ ان سے روایت کے ذریعے بھی دین کو ضرر ہوا اور عقائد کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی اور خیالات کے لحاظ سے بھی‘‘۔
اس کے بعد اس کی قدرے تفصیل فرمائی اور فرمایا کہ :
’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو ’’لا الہ الا اللہ‘‘ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا تھا جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم پاخانہ ، پیشاب وغیرہ کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے ننگے کیونکر ہوں؟ یہ انتہا ہے۔ اور ان کو مجاہدات وریاضات کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور یہ قوت بہ فیض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تھی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم اور تابعینؒ میں بھی تھی مگر صحابہ سے کم، لیکن تبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی اور اس کمی کی تلافی کے لیے بزرگوں نے مجاہدات اور ریاضات ایجاد کیے۔ ایک زمانہ تک تو محض وسائل غیر مقصودہ کے درجہ میں رہے، مگرجوں جوں خیر القرون کو بعد ہوتا گیا، ان میں مقصودیت کی شان پیدا ہوتی رہی اور وقتاً فوقتاً ان میں اضافہ بھی ہوتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین میں بے حد بدعات علمی وعملی اور اعتقادی داخل ہو گئیں۔ محققین صوفیہ نے ان خرابیوں کی اصلاح بھی کی، مگر اس کا نتیجہ صرف اتنا ہوا کہ ان بدعات میں کچھ کمی ہو گئی، لیکن بالکل ازالہ نہ ہوا‘‘۔
حضرت نے مصلحین میں شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور مجدد الف ثانی اور سید احمد قدست اسرارہم کانام خصوصیت سے لیا اور فرمایا کہ ’’ ان حضرات نے بہت اصلاحیں کی ہیں، مگر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا‘‘۔ (حکایات اولیاء، المعروف بہ ارواح ثلاثہ ، ص ۲۹۷ تا ۲۹۹، حکایت نمبر : ۲۹۷)
یاد رہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے بعد گزشتہ دو سو سال میں امام ربانی حضرت گنگوہی ؒ جیسی جامع ومحقق کوئی ہستی نظر نہیں آتی۔ حضرت گنگوہی ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت تھانوی ، حضرت مدنی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ سمیت تقریباً ہمارے پورے ہی حلقے کے شیخ ورہبر ہیں اورآپ کا یہ ملفوظ زندگی کے آخری دنوں کا ہے، گویا پوری زندگی کے تجربات کا خلاصہ ہے۔ حضرت گنگوہی ؒ نے بڑی گہری بات فرمائی ہے۔ جس کی تصوف تاریخ پر وسیع نظر ہو، وہ حضرت کی بصیرت کی گہرائی کو سمجھ سکے گا۔ حضرت امام ربانیؒ نے چند جملوں میں گویا پوری تاریخ کا عطروخلاصہ بیان فرمادیا ہے۔
تصوف کے بے شمار سلسلے، خلاف شریعت اور باطل محض رہے ہیں، جیسے مداری، روشنی ، حلولی، حلاجی، قلندری ، ملامتی وغیرہ وغیرہ اور صحیح سلسلوں میں بھی بعد والوں کی ذرا سی بے احتیاطی یا غلو سے بے شمار خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوئے۔ دور کیوں جائیے، برصغیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ سے لے کر تمام اکابر اولیا ء اپنے اپنے زمانہ کے صحیح اہل حق ہی تو تھے۔ ا نہوں نے ساری زندگی شریعت کی اتباع اور مخلوق کو اللہ سے ملانے میں گزاری، مگر آج تقریباً سب ہی آستانے ومزارات شرک وبدعات کے گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ تصوف میں جب بھی بگاڑ وفساد آیا، کسی شخصیت کے ساتھ عقیدت میں غلو کے نتیجہ میں آیا۔ اکثر بزرگان دین اور اولیا ء کبار کی کچھ پشتوں کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کی تعظیم میں غلو کر کے ان کی ہستی کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا کہ اب تا قیامت انہیں روزی کے لیے پسینہ بہانے ومحنت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خواجہ کے نام پر حرام خوری کرنی ہے۔
حضرت مجدد الف ثانی ؒ سے بڑھ کر بدعات ورسوم وخرافات اور شیعیت کے خلاف کس نے لکھا ہوگا؟ مگر تیسری پشت ہی میں ان کی اولاد کے متعدد بزرگ دعوے دار تھے کہ وہی آج کے ’’قیوم‘‘ ہیں، زمین وآسمان انھی کے سروں پر قائم ہیں۔ ’’روضۃ القیومیۃ‘‘ جیسی کتاب اٹھا کردیکھیں ! قیوم کی تعریف وصفات میں صفحے کے صفحے بھرے پڑے ہیں، ساری الوہی وخدائی صفات’’قیوم‘‘ کو حاصل ہیں۔ قیومیت کا منصب کیا ہے ؟ اس کی توضیح وتشریح احسان مجددی نے اپنی کتاب ’’روضۃ القیومیۃ‘‘ میں کی ہے جو سلسلہ مجددیہ کے مطابق قیوم رابع کے خلیفہ تھے۔ لکھتے ہیں:
’’ قیوم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ماتحت اسماء وصفات، شؤنات، اعتبارات اور اصول ہوں اور تمام گزشتہ وآئندہ مخلوقات کے عالم موجودات، انسان وحوش، پرند ونباتات، پھر ذی روح، پتھر ودرخت، بحر وبر ہر شے، عرش وکرسی، لوح وقلم، سیارہ، ثواقب، سورج، چاند، آسمان بروج سب کے اس کے سایہ میں ہوں۔ افلاک وبروج کی حرکت وسکون، سمندر کی لہروں کی حرکت، درختوں کے پتوں کا ہلنا، بارش کے قطروں کا گرنا، پھلوں کا پکنا، پرندوں کا چونچ پھیلانا، دن رات کا پیدا ہونا، گردش کنندہ آسمان کی موافق وناموافق رفتار، یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ بھی ایسا نہیں جو اس کی اطلاع کے بغیر گرتا ہو، زمین کی حرکت وسکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں‘‘۔ (۱؍ ۹۴)
بس پڑھتے جائیں! یہ سب عقیدت میں غلو کی کارستانی ہی تو ہے۔ یہ ساری خرابیاں تعظیم میں غلو اور اعجوبہ پسندی کی ذہنیت سے پیدا ہوئیں، اس لیے عوام کی ذہنیت کی نگہداشت علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک بار حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحبؒ نے فرمایا:
’’ جو اللہ کو اس کی ظاہری قدرت سے پہچانے گا ( جسے قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے)، مردہ زمین کو زندہ کرنا، جہازوں کا سمندر میں چلانا، آسمان کا بغیر ستون کے قائم کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط ہوگا اور جو عجوبہ پسندی (کشف وکرامات) کے دل دادہ ہوں گے، وہ سب دجال کے چیلے بن جائیں گے کہ دجال اس قسم کے سارے عجوبے وخارق چیزیں لے کر آئے گا، حتی کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے گا تو زمین کا ایک جھٹکا ( زلزلہ) مدینہ منورہ میں مقیم اس قسم کے ۷۰؍ ہزار عاشقان رسول کو دجال کی گود میں پھینک دے گا اور وہ سب دجال کے چیلے بن جائیں گے۔ ‘‘
اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے ذہنوں کو اس طرح کے تماشوں کے بجائے عملی کاموں کی طرف لانے کی سعی کریں۔ دین کے دیگر شعبوں مثلاً تعلیم وتعلم، دعوت وتبلیغ وغیرہ میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مگر ان کا نقصان تصوف کے نقصان سے بہت کم ہوتا ہے، کیوں کہ تصوف کا بگاڑ براہ راست شرک وبدعات پر منتج ہو تاہے۔ دنیا میں جتنی بدعات ہیں، سب نیک نیتی اور اچھے جذبات سے شروع ہوتی ہیں جیسے شیخ کے انتقال پر ان کی تعلیمات وطریقہ کی حفاظت کے لیے ان کے وفات کے دن خلفا ومتعلقین کا جمع ہونا، یا اگر کہیں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے اور جمعہ آیا تو کسی نے کہا کہ چونکہ یہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ایک شخص سورہ کہف جہراً پڑھ لے تو باقی سب کو سننے کا ثواب مل جائے گا یا ایصال ثواب کی رسوم وغیرہ۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ کے بعد ہمارے اکابرین کا اصل مشغلہ تو تعلیم وتعلم، دعوت وتبلیغ، تزکیہ واصلاح، تصنیف وتالیف وغیرہ تھا، لیکن خدا سے تعلق بڑھانے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے اور کمال اخلاص کے حصول کے لیے ضمناً ساتھ ساتھ ذکر وفکر بھی تھا۔ ان اکابرین کا اوڑھنا بچھونا علم دین خصوصاً علم حدیث وفقہ تھا، سیرت واحوال صحابہؓ پر گہری نظر تھی، اس لیے اگر تصوف کی راہ سے کوئی غیر شرعی ، رسمی یا عجمی شے آتی تو فوراً کٹ جاتی تھی، مگر علوم حقیقی کے زوال کے زمانہ میں اگر گہری نگہداشت نہ کی گئی تو خاموشی سے بظاہر بے ضرر نظر آنے والی رسوم داخل ہو کر اپنی جگہ بنالیں گی، پھر ان کا ازالہ مشکل ہو جائے گا۔
بندہ نے مولانایوسف متالا صاحب کو ایک ملاقات میں کہا تھا کہ : پیر تو پیر ہوتا ہے، دیوبندی یا بریلوی میں اب فرق کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بھی غیر شعوری طور پر اسی راہ پر چل پڑے ہیں۔ اپنی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں غلو وعقیدت کا اس طرح مظاہرہ ہونے لگا ہے کہ علما بھی، جن سے توقع ہوتی ہے کہ وہ حزم واحتیاط ، توازن واعتدال کو قائم رکھتے ہوئے عوام کو عقیدت کے سطحی مظاہروں سے ہٹا کر عملی امور کی طرف متوجہ کریں گے، وہ بھی عوام کے ریلے میں بہہ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، اگر یہ رخ چل پڑا تو ہر شخص’’ کھیڑا لو باپو‘‘ بننے کی سعی کرے گا جس کا دعویٰ تھا کہ ہر بیماری وپریشانی سے نجات کے لیے اس کی پھونک اتنے میل تک جاتی ہے۔ جب وہ کسی علاقے میں آتا تو وہاں کی مساجد کے حوض پانی سے خالی ہو جاتے تھے۔
بندہ کو اپنی ۶۶ سالہ زندگی میں ہند و بیرون ہند کے بہت سے بزرگوں اور اکابر اولیا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اکثر بزرگوں کو قریب سے دیکھا اور ان کی خدمت میں کئی کئی دن رہنا نصیب ہوا، جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت مولانا منظورنعمانی، حضرت مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی، حضرت مولانا عبدالحلیم جونپوری (رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) وغیرہ۔ ان اکابرین کے دوروں کے مواقع پر اس طرح کی ہنگامہ خیزی اور بعض دوستوں کے الفاظ میں’’ مرجعیت ومقبولیت ‘‘ کہیں نہیں دیکھی جس کا مظاہرہ آج کل کے بعض پیران کرام کی آمد کے موقع پر ہوتا ہے۔ گجرات میں ان بزرگوں کے دورے بھی نظر کے سامنے ہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ؒ نے گجرات کے مدرسوں کا سفر فرمایا تھا۔ محض اساتذہ کرام اور طلبہ ہوتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ کی متعدد تقریریں سورت کے ’’ نگین چند ہال‘‘ میں سنیں۔ مشکل سے ۴؍۵ سوا فراد ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا صدیق باندوی،حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی (رحمہم اللہ تعالیٰ) وغیرہ کے دوروں پر بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت جی کے دوروں کے مواقع پر عالمی اجتماعات میں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، مگر شہروں اور بستیوں میں سیکڑوں یا زیادہ سے زیادہ ہزاروں کی تعداد ہوتی۔
حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کی ایک نہایت قیمتی نصیحت یاد آتی ہے۔ فرمایا: مولوی صاحب! دو: راستے ہیں۔ ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا ، دوسرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒ کا۔ ایک میں عوام کی حفاظت ہے، دوسرے میں خواص کی منفعت ۔ آپ میزان کر لیں کہ دونوں میں کیا عزیز ہے، عوام کی حفاظت یا خواص کی منفعت؟
اس زمانہ میں ایک بے اعتدالی جو کچھ عرصہ سے ہم دیوبندیوں میں بھی بڑھ رہی ہے، وہ یہ کہ ہم اسلام کو اپنے بزرگوں کے حوالے سے پیش کررہے ہیں، جب کہ اسلام جب بھی پیش کیا جائے گا، قرآن وسنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ کرامؓ کے حوالے سے پیش کیاجائے گا، نہ کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب اور دوسرے اکابر کے حوالے سے، جیسا کہ ساؤتھ افریقہ والوں نے انٹر نیٹ پر اپنے اپنے بزرگوں کے معمولات، کشف وکرامات واحوال کی بھرمار کر رکھی ہے۔ اکابرین کے معمولات اور طریقہ کار یقیناًبہت اچھے اور مفید ہیں، مگر پوری امت اس کی مکلف نہیں۔ اگر کسی بزرگ نے اپنے تجربات اورا جتہاد کی روشنی میں دین کی تین باتوں یا چھ باتوں کو محور بتاکر ان پر زور دیا تویقیناًیہ ان کا حق ہے، مگر عوام الناس کے سامنے ہمیشہ قرآن وسنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے حوالے سے ہی اسلام کو پیش کیاجائے گا، نہ کہ بزرگوں کے ذوقی نکات کے حوالے سے۔ خاص طور پر تصوف کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے۔ تصوف کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ تصوف چاہے جہاں سے چلے، چند پشتوں کے بعد اس کا مآل (انجام) وہی ہوتا ہے جو اکابر اولیا ء اللہ کے مزارات پر نظر آتا ہے کہ جب ٹھوس علم نہ رہے تو آہستہ آہستہ عقیدت میں غلو پیدا ہوکر بدعات ورسوم ، دین بن جاتی ہیں۔
برصغیر کے مسلم فاتحین کی اکثریت نو مسلم تھی اور اسلامی زندگی سے ناآشنا، خاص طور پر مغلوں کا دور دینی اعتبار سے بڑا ہی منحوس اور نامبارک ثابت ہوا۔ مغل حکمران ہمایوں کے دور حکومت سے لے کر آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کے عہد تک تقریباً تین سو سال کے طویل عرصہ میں مسلم معاشرہ پر شیعیت کی زبردست یلغاررہی۔ حکومتی عہدے دار، علوم، نصاب تعلیم اور سب سے بڑھ کر تقیہ بردار شیعی شیوخِ تصوف کی خانقاہوں کے ذریعے سے (خواجہ اجمیری ؒ کے خلفا میں کئی شیعہ تھے) مسلم عوام کے ذہنی استحصال کے نتیجے میں امت مسلمہ کے عوام وخواص کے دلوں میں قرآنی احکام وہدایات اورحدیث وسنت کی اہمیت کم ہوتے ہوتے تقریباً معدوم ہوگئی تھی اور اس کی جگہ اولیا ء کرام اور بزرگان دین کے بے سند قصص وحکایات اور ملفوظات نے لے لی تھی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی ؒ لکھتے ہیں کہ :
’’ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ اس تاریخ سے بے گانہ ہو کر اس کو فراموش کر بیٹھے۔ ہمارے اہل وعظ وارشاد اور اہل قلم ومصنفین نے اپنی تمام تر توجہ اولیاء متاخرین کے واقعات اور ارباب زہد ومشیخیت کی حکایات بیا ن کرنے پر صرف کردی اور لوگ بھی اس پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ وعظ وارشاد کی مجالس، درس وتدریس کے حلقے اوراس دور کی ساری تصانیف اور کتابیں ان ہی واقعات سے بھر گئیں اور سارا علمی سرمایہ صوفیاء کرام کے احوال وکرامات کی نذر ہو گیا‘‘۔ ( مقدمہ حیاۃ الصحابہ اردو ، ۱؍۲۰)
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ، اس کی مجموعی صورت حال کا نقشہ علامہ سید سلیمان ندویؒ نے یوں کھینچا ہے:
’’سلطنت مغلیہ کاآفتاب لب بام تھا، مسلمانوں میں رسوم وبدعات کا زور تھا، جھوٹے فقرا ء اور نام ونہاد مشایخ اپنے اپنے بزرگوں کی خانقاہو ں میں مسند بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے، مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق وحکمت کے ہنگاموں سے پر شور تھا، فقہ وفتاویٰ کی لفظی پرستش ہر مفتی کے پیش نظرتھی، تحقیق وتدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم تھا، عوام تو عوام، خواص تک قرآن پاک کے معانی، مطالب اور احادیث کے احکام وارشادات اور فقہ دین سے بے خبر تھے‘‘۔ (مقالات سلیمانی، ص ۴۴)
آج جس قدر قرآن وسنت کا چرچا ہے، اسی طرح عجمی تصوف سے نبوی تزکیہ واحسان کی طرف توجہ مبذول ہونا بھی سب حضرت شاہ ولی اللہ ؒ اورآپ کے خانوادہ ؒ کی برکت ہے۔ شاہ ولی اللہ ؒ کے والد محترم شاہ عبدالرحیم ؒ اور چچا شیخ محمد رضا ؒ دونوں اہل طریقت میں تھے۔ معاصر تذکروں اور ’’روضۃ القیومیۃ‘‘ میں ان کا تذکرہ مشایخ تصوف کے ضمن میں ہوا ہے نہ کہ علماء کی صف میں۔ ایسی صورت میں حضرت شاہ ولی اللہ ؒ کی تصوف سے غیر معمولی دلچسپی کوئی تعجب خیزبات نہیں۔ شاہ ولی اللہ کو تصوف کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا بھی احساس تھا اور اس میں شامل عجمی افکار اور شیعیت کے باطل نظریات کی زہرناکی سے بھی پوری طرح آگاہ تھے، چنانچہ آپ نے عہد زوال کے تصوف کی، جو اسلامی احسا ن وتزکیہ کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اصلاح کی پوری کوشش فرمائی۔ بعد کے دور میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تصوف کے متعلق تفصیلی کتب لکھ کر شاہ ولی اللہ ؒ کے کام کو آگے بڑھایا اور شاہ ولی اللہ ؒ کے نقطۂ نظر کی وضاحت وترجمانی فرمائی اور یہی کام ہر دور میں علماء کرام کو کرنا ہوگا۔
حضرت شاہ ولی اللہ ؒ نے اپنے وصیت نامہ میں تیسری وصیت یہ فرمائی کہ:
’’اس زمانہ کے مشایخ جو طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہیں، ان سے بیعت ہرگز نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی بیعت ممنوع ہے۔ اس سلسلہ میں عوام الناس کے غلو عقیدت کی پروا نہ کریں، نہ ان سے وابستہ کرامات کے و اقعات پر یقین کریں، کیوں کہ اکثر عوام الناس میں غلوِ عقیدت محض رسمی ہوتا ہے اور امور رسمیہ کاحقیقت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا‘‘۔ ( رود کوثر ، ص۵۸۰)
مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن ندویؒ نے اپنی کتاب’’ تاریخ دعوت وعزیمت‘‘ میں حضرت شاہ ولی اللہ ؒ کی تحریک کا خلاصہ سات نکات میں بیان فرمایا ہے جس میں سب سے اہم ابتدائی دو نکات ہیں۔ ایک اصلاح عقائد ودعوت قرآن اور دوسرا حدیث وسنت کی اشاعت وترویج۔ شاہ ولی اللہ ؒ اوران کے خانوادے کی برکت سے قرآن وسنت، سیرت وفقہ، تزکیہ واحسان، دعوت وجہاد کے شعبے زندہ ہوئے۔ حضرت سید احمد شہیدؒ کے ایک سفر حج میں لاکھوں نے توبہ کی اور ہزاروں مسلمان ہوئے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے شیعیت کے (جو پور ے ملک پر حاوی ہو گئی تھی ، حتی کہ اکثر بزرگان دین کی گدیوں پر براجمان سجادہ نشین تقیہ کے پردہ میں شیعی ذہنیت کے حامل تھے اور آج بھی ہیں) مراکز وقلعوں پر جارحانہ حملے کر کے انہیں دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا۔ یہ ولی اللہ تحریک ومکتب فکر، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے نواسے شاہ محمد اسحاق اور شاگرد رشید مولانا رشید الدین دہلویؒ کی درسگاہ سے ہوتی ہوئی مولانا مملوک علی تک پہنچی اور ؒ پھر آپ کے صاحبزادے مولانا یعقوب نانوتوی اور شاگرد رشید حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی ؒ وغیرہ کے ذریعے سے پھل پھول کر ایک تناور درخت بن گئی۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ولی اللہی مکتب فکر کے حقیقی وارث اور علمبردار علماء دیوبند تھے۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر حضرت شیخ الہند کے دورتک امت پنے کی ذہن سے کام ہوا اور عملی طور پر پوری امت کی فکر کی گئی۔ پھر فکر وجہد برصغیر تک محدود ہوگئی اور برصغیر کے تین ملک ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقے تک۔ اب صورت حال یہاں تک پہنچ گئی کہ یہاں لندن میں برصغیر کے تینوں ممالک کے مشایخ وعلماء کی فکری حدود اپنے اپنے قبیلے وقوم یاضلع تک سمٹ چکی ہیں۔
تصوف میں جب کبھی مشیخیت ، روحانیت پر غالب آئی، تصوف انتہائی نقصان دہ بن گیا۔ جس طرح حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تجدیدی تحریک مشیخیت کے ذہن سے پیدا شدہ نظریہ قیومیت کے سراب میں گم ہوگئی، اسی طرح اب حضرت شاہ ولی اللہ ؒ کی برپا کر دہ تحریک (تعلیم قرآن، سنت اور دعوت) علماء کی غفلت سے پھر مشیخیت (شخصیت پرستی کے غلو) میں گم ہونے جارہی ہے۔ آج کل علما نے شرک وبدعات کا رد چھوڑ رکھا ہے جس کی وجہ سے اہل بدعات کا پھر غلبہ ہو گیا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ مشیخیت یعنی اپنے مقرب ہونے کا غرہ ہے۔ اس مشیخیت کی وجہ سے ہم اہل بدعت کے مماثل بنتے جارہے ہیں۔ انگلینڈ کے ایک بڑے مشہور شہر میں دو پیر صاحبان نے اپنا اپنا علاقہ تقسیم کررکھا ہے۔ ایک کا اعلان دوسرے کی مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ دنوں جب حضرت مولانا طلحہ صاحب تشریف لائے تو دونوں کے ہاں ان کا پروگرام تھا۔ ایک جگہ پہنچے تو شاید تھکان کی وجہ سے آرام کے لیے چلے گئے۔ دوسرے پیر صاحب سینکڑوں مصلیوں کے ساتھ آدھی رات تک اپنی ہی مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ پھر باتیں چلیں کہ فلاں نے آنے نہیں دیا۔ یہ دونوں پیر صاحبان جب نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو متعدد لوگ مشایعت کے لیے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ اگر مریدوں میں سے کسی کونماز میں دیر ہو جائے تو وہ نماز توڑ کر پیر صاحب کی مشایعت کو ضروری سمجھتا ہے۔ تصوف کی منزل کا تو پہلا قدم ہی اپنے نفس وانانیت کو توڑنا ہے۔ یہاں درجن بھر قطب الاقطاب کا یہ حال ہے کہ عالم اسلام یا برصغیر کی کوئی بھی بڑی شخصیت آجائے، یہ اپنے گھر انتظا ر کرتے ہیں اور خود جا کر ملنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ بندہ نے تقریباً دو سال پہلے مولانا عبداللہ پٹیل صاحب کو عرض کیا تھا کہ اس مشیخیت کی خبر لیجیے! ورنہ بندہ اپنے انداز میں کچھ کہے گا تو سختی ودرشتی کی شکایت نہ کیجیے گا۔ بندہ کے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی مشیخیت ہے۔
بندہ جب ۱۹۷۵ء میں تبلیغی مرکز کے امام کے طور پر یہاں (لندن) پہنچا تو مرکز پر، مسجد واسلامک سنٹر میں رمضان المبارک میں حضرت شیخ الحدیث ؒ کے معمولات کے عنوان سے ایک چارٹ دیکھا۔ انہی دنوں علاقہ میں ایک پاکستانی دوست کے جوان بچے کا حادثہ ہو گیا۔ بندہ چند تبلیغی احباب کے ہمراہ تعزیت کے لیے ان کے ہاں گیا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے اور مسجد کے خطیب صاحب، جو بریلوی مکتب فکر کے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ شاید ان کی مسجد میں بھی چارٹ بھیجا گیا ہوگا۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہنا شروع کیا: ہم نماز کے بعد جہری ذکرکریں تو بدعت،ان کے شیخ الحدیث کے ہاں روزانہ عصر کے بعد ذکر جہری ہوتا ہے، وہ سنت۔ ہم ختم خواجگان کریں تو بدعت، ان کے شیخ کے ہاں روزانہ ظہر کے بعد ختم خواجگان ہوتا ہے، وہ سنت۔ ہم بزرگوں کی قبروں پر جائیں تو بدعت، ان کے شیخ، حضرت گنگوہیؒ کی قبر پر دو گھنٹے مراقبہ کریں، وہ سنت۔ ہم کریں تو بدعت، دیوبندی کریں تو سنت۔ چند دنوں کے بعد ہندوپاک کے متعدد اکابر علماء تشریف لائے۔ ا ن میں حضرت مفتی زین العابدین ؒ بھی تھے۔ بندہ نے اکابر سے اس گفتگو کا تذکرہ کیا تو تقریباً سب ہی نے کہا : ان خطیب صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی۔
اسی طرح حضرت شیخ الحدیث کی یہاں آمد ثانی کے موقع پر خلفا کی طرف سے مبشرات پر مشتمل ایک کتابچہ چھاپا گیا جس کا عنوان غالباً ’’ محبتیں‘‘ تھا۔ اس پر سلفی حضرات کے ماہنامہ ’’ صراط مستقیم‘‘ میں کئی قسطوں میں سخت تبصرہ چھپا کہ ان کے شیخ جب افریقہ، ری یونین، انگلینڈ تشریف لے جاتے ہیں تو سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم،خلفائے راشدین اور دیگر اکابر صحابہ شیخ کے استقبال، انتظامات اور دیگر خدمات کے لیے پہنچتے ہیں۔ ا ن دیوبندیوں نے سرو رد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو شیخ کا خادم بنا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بہت سی باتوں پر جب کبھی بندہ نے مولانا یوسف متالا کو ٹوکا تو ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا : غلطی ہو گئی۔
ماضی میں بزرگان دین اپنی خانقاہوں میں خاموشی سے افراد سازی فرماتے تھے۔ ہر میدان کے رجال کار تلاش کر کے انہیں کام میں لگاتے تھے، ان کی سر پر ستی، وسائل سے اعانت اور ہمت افزائی فرماتے تھے اور ان سے مختلف میدانوں میں اجتماعی کام لیتے تھے، جیسے دونوں حضرات راے پوری، تبلیغی جماعت، جمعیت علماء، مجلس احرار، ختم نبوت، جنگ آزادی کے مجاہدین، سیاسی وخدمت خلق کے میدانوں میں کام کرنے والے اور مختلف عملی وتصنیفی کام کرنے والے حضرات۔ دیوبند، مظاہر، ندوۃ چھوٹے بڑے مدارس ومکاتب کی سرپرستی فرماتے۔ اس طرح یہ حضرات خاموشی سے ملت کو منضبط ومتحد کرتے تھے۔ اول تو سفر بہت کم فرماتے ۔ اگر کرتے تو عموماً دین سے دور اور غربت زدہ علاقوں میں کرتے۔ اب حال یہ ہے کہ ایک ایک شیخ کے خلفا، پھر ہر خلیفہ کے درجنوں خلفا، امت کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار رہے ہیں۔ آج عالم کفر عالمگیریت کے دور میں پہنچ کر ایک ایک مسلم ملک، قوم، طاقت اور ادارہ کو مل کر اقوام متحدہ کے زیر سایہ باری باری تباہ کررہا ہے۔ ادھر اللہ سے تعلق اور روحانیت کے دعوے دار ایک دوسرے کے مریدوں کی چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصود متاع دنیا اور دنیوی وجاہت بن گیا ہے۔ ان اللہ والوں کے زیادہ تر اسفار گجرات اور دنیا بھرمیں پھیلے ہوئے گجراتی اہل ثروت کی طرف ہوتے ہیں۔ خلافت کی ریوڑیاں بھی زیادہ ترانہی لوگوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ( ایک مولوی کو ایک نہیں، کئی کئی خلافتیں)۔ بھارت کے بیس کروڑ مسلمان نظر التفات سے عموماً محروم رہتے ہیں۔ گزشتہ سال دُبیؔ کے چند دوستوں نے بتایا کہ فلا ں حضرت اپنے آدھ درجن بیٹوں وپوتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کی تشریف بری کے بعد دیکھا کہ بہت سوں کے ہدایا میزبان کے گھر پڑے تھے، کیونکہ ۶؍ ٹکٹوں پر زیادہ حضرت صرف قیمتی ہدایا ہی ساتھ لے جا سکے۔ یہاں لندن میں ہر خلیفہ نے اپنی ضروریات کے لیے چند اہل ثروت کو چن رکھا ہے اور یہ اللہ والے عموماً کسی کروڑ پتی کے ہاں قیام فرماتے ہیں، کسی غریب مرید کے ہاں شاذ ونادر ہی نزول فرمائیں گے۔ حقیقی روحانیت ہمیشہ فقر وفاقہ میں مست اور خوش رہتی ہے اور مشیخیت پیسوں کا کھیل بن جاتی ہے۔
سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہربرائی اور گناہ کی جڑ دنیا کی محبت کو اور امت کے لیے فتنہ ، عورت اور مال کو قرار دیا۔ چودہ سو سالہ تاریخ گواہ ہے، اہل دین میں ہمیشہ فتنہ (فساد وبگاڑ) مال کی جہت ہی سے آیا ہے۔ کسی قوم اور ملت کی تباہی وزوال کی بنیادی وجہ حکمرانوں اور علما کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اگر ان دو میں سے ایک بھی اپنا فریضہ صحیح طور پر ادا کر رہا ہوتو فساد وبگاڑ نصف رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ امت اور اس کے مشایخ وعلماء (احبار ورہبان) بنی اسرائیل کی قدم بقدم پیروی کریں گے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے علماء ومشایخ کے حالات دیکھ لیں، کیا ہم انھی کے نقش قدم پر نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آج کل اکثر مولوی مال بٹورنے اور جمع کرنے والی آیت ادھوری پڑھتے ہیں اور وَالَّذِیْنَ یَکْنِزُونَ الذَّہَبَ وَالْفِضَّۃَ سے شروع فرماتے ہیں، جب کہ آیت میں اصل وعید ودھمکی علما و مشایخ (احبار ورہبان) ہی کی حرام خوری کے متعلق ہے۔
آج غریب آدمی اولیاء اللہ سے مصافحہ تو درکنار زیارت بھی بمشکل کر سکتا ہے۔ میرے ایک پاکستانی دوست جو یہاں بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہیں، کہنے لگے: میں پاکستان میں فلاں فلاں مشایخ وبزرگوں اور اکابرین سے مل کر آرہا ہوں، سب ہی نے مجھ پر بڑی شفقت کی اور خوب اکرام فرمایا۔ بندہ نے عرض کیا: کیوں نہ کرتے، آپ انگلینڈ سے جو گئے تھے، اونچے عہدے پر جو ہیں۔ اب ایک بار اور جائیے، دیہاتی لباس میں اور سب سے عرض کیجیے: حضرت! چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرض ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں، دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر دیکھیے، کس طرح آپ کو دسترخوان پر ساتھ بٹھا کر اکرام فرماتے ہیں۔
آج کے پیر صاحبان، مہتمم صاحبان، تبلیغی جماعت کے امرا کو اگر موٹا سا ہدیہ دیا تو دسترخوان پر داہنی جانب عزو وقار کے ساتھ بٹھائیں گے، بلکہ دست مبارک سے لقمہ دیں گے۔ بدقسمتی سے غریب ہیں تو دور سے زیارت ہی کو خوش نصیبی اور جنت کا ٹکٹ سمجھئے۔ بھوپال کے حضرت مولانا حبیب ریحان ندوی ( شیخ الحدیث تاج المساجد) جب کبھی یہاں تشریف لاتے، ایک رات بندہ کے ہاں گزارتے اور بے تکلفی سے باتیں ہوتیں۔ تقریباً پندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے، کہنے لگے: آج کے بعض مولوی اور پیروں سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں۔ اس بات پر بندہ کی مولانا سے جھڑپ ہو گئی۔ مجھے اللہ معاف کرے، بہت سخت سست کہہ دیا اور یہاں تک کہہ دیا : یہ علماء دشمن مودودیت بول رہی ہے۔ (آپ مولانا مودودی صاحب کی تحریروں سے بھی متاثر تھے) وغیرہ وغیرہ۔ ادھر بدقسمتی سے ان پندرہ سالوں میں ایسے تجربے ہوئے کہ الامان والحفیظ۔ ۳۰، ۳۰ لاکھ کی کوٹھیاں بن رہی ہیں۔ انگلینڈ میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک کالی ٹیکسی سے تشریف لے جاتے ہیں ( جو اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ یہاں والے بھی ہمت نہیں کرتے۔) ان کی جیبوں میں دنیا بھر کے ہوائی جہاز کے اوپن ٹکٹ پڑے رہتے ہیں۔ گھر کے نقشے ،عیش وعشرت ہی نہیں، عیاشی تک پہنچے ہوئے ہیں۔غرض جس قدر خلفاء کرام، عالی یشان جامعات اور علماء کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسی قدر ہدایت گھٹتی جا رہی ہے۔
اب یہاں ہم دیوبندیوں میں ایک بدعت یہ شروع ہوگئی ہے کہ یہ اللہ والے اپنے مدرسے سے تمام فارغ ہونے والوں کو خود ہی بیعت فرما لیتے ہیں کہ ہماری مرغیوں کے انڈے ہم ہی کھائیں، دوسرا کوئی کیوں فائدہ اٹھائے، اس لیے ان کے طلبہ پوری امت کے علماء و اہل اللہ سے کٹ کر صرف اپنے پیر سے مرتبط رہتے ہیں۔ کوئی ایسا عالم دین یا بزرگ جو ان کے شیخ کو قطب الاقطاب نہ مانتا ہو، اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے جب کہ ہمیشہ صحیح روحانیت والوں کا طریقہ یہ تھا کہ طلبہ کی ذہنی مناسبت وصلاحیت کے اعتبار سے انہیں اہل اللہ کے حوالے فرماتے، جیسے حضرت رائے پوری ؒ نے اپنے خادم خاص حضرت مولانا عبدالمنان دہلویؒ کو حضرت شیخ الحدیث ؒ کے پاس اور حضرت تھانویؒ نے اپنے پاس مرید ہونے کے لیے آنے والے مولانا عبدالماجد دریا بادی کو حضرت مدنیؒ کے پاس بیعت کے لیے بھیجا۔ اب اس زمانہ کے اللہ والوں کی دیکھادیکھی تبلیغی ذمہ داربھی زور دینے لگے ہیں کہ بھائی، ہمارے کام کرنے والوں کو تو حافظ پٹیل صاحب ہی سے بیعت کرنی چاہیے، تب ہی تبلیغی کام کا پورا فائدہ ہوگا۔ یہ سارے کرشمے مشیخیت کے ہیں جو سچی روحانیت سے بہت دور ہے۔ اگر یہ مشیخیت اسی طرح بڑھتی رہی تو اندیشہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ ؒ سے شروع ہونے والی توحید وسنت، قرآن وحدیث کی اشاعت کی دعوت اور سچی روحانیت کا یہ سفر ترقی معکوس کر کے شاہ صاحب سے پہلے والی جہالت اولیٰ پر نہ منتج ہو جائے۔ آج دیوبندیوں کے ہاں بھی اپنے بزرگوں اور اکابرین کانام بیچ کرمال بٹورنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج مال بٹورنے کا یہ سب سے سہل نسخہ یہی بن چکا ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اب یہ مشیخیت یاجعلی روحانیت کامیاب نہیں ہوسکے گی، بلکہ منہ کی کھائے گی۔ ہمارے اکابر کی ڈھائی سو سالہ قربانیاں اور جدوجہد رائیگاں نہیں جائے گی۔ اب صرف قرآن وسنت، سیرت نبوی وصحابہ کی بات ہی چلے گی، نہ کہ بعد والی عجمی افکارواعمال کی ملاوٹ زدہ مشیخیت، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دیوبندی اس مشیخیت وشخصیت پرستی کے مہلک سراب سے نکل کر اپنے اصل بزرگوں کی طرف لوٹیں۔ وماذلک علی اللہ بعزیز۔
تنقیدی جائزہ یا ہجوگوئی؟ (۲)
محمد رشید
۷۔ سابقہ سطور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مضمون نگار کس بے رحمی سے ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے درویش منش انسان کو قارونی گروہ کا خاموش حمایتی ثابت کرنے کی کوشش کرچکے ہیں۔اور پھر وہ یہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اور مارکس کے سوا علما و سکالرز کی اکثریت قارونی گروہ کی مخالفت سے اجتناب کے گناہ میں ملوث رہی ہے۔لیکن جب حضرت انعام یہ دیکھتے ہیں کہ محاضرات معیشت میں محترم غازی صاحب افراد معاشرہ کی کفالت اور ان کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا ذمہ داراسلامی ریاست کو قرار دیتے ہیں اور پھراسلاف کے حوالوں کے ساتھ قارونی گروہ کے خلاف بغاوت پران الفاظ میں اکساتے ہیں :
’’فقہائے اسلام میں سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے جن میں علامہ ابن حزم کا نام بہت مشہور ہوگیا ہے کہ اگر ریاست اپنے ان تقاضوں کو پورا نہ کرے یا ریاست ان فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور کوتاہی اختیار کرے اور معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کو روزی پیٹ بھر کر نہ ملتی ہو، ایسے لوگ موجود ہوں جن کے پاس تن ڈھانپنے کو لباس نہ ہو، سر چھپانے کو چھت نہ ہوتو وہ زبردستی خود باوسیلہ لوگوں سے اپنا حق وصول کرسکتے ہیں۔‘‘ (محاضرات شریعت صفحہ182-183)
تو صاحب محاضرات کے اس خوبصورت چناؤ کی تحسین کرنے کی بجائے عقل کل حضرت انعام کی زبان طعن اس طرح دراز ہوتی ہے:
’’ڈاکٹر صاحب بندوق چلانا چاہتے ہیں لیکن ابن حزمؒ کے کندھوں پر رکھ کر۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے علماء و سکالرز کی اکثریت اس طرح کے معاملات میں طرح مصرع ملنے پر بھی غزل کہنے سے گریز کرتی ہے؟ ان کا یہ سہما سہما معذرت خواہانہ اندازشاید اس لیے ہے کہ ماضی میں سوشلزم کی مخالفت برائے مخالفت میں خود انہی مقاصد(کفاف وغیرہ) سے چشم پوشی کرتے رہے ہیں۔‘‘
یعنی عقل کل حضرت انعام کو بڑی تکلیف اور شدید دکھ ہے کہ جس طرح ماضی میں علماء عوامی حقوق کے بارے میں خاموش رہے ہیں تو اسی طرح اب بھی کوئی نہ بولے۔لہٰذا اب اگر اعلیٰ ترین علمی حلقوں سے محترم غازی صاحب اس معاملے پر علم و برہان اور دلیل و سند کی قوت سے بولتے ہیں تو اسے وہ ’’دوسروں کے کندھوں پر بندوق چلانا‘‘، ’’سہما سہما معذرت خواہانہ انداز‘‘، ’اور ’’ماضی میں چشم پوشی کے جرم‘‘ کا قصور وار ٹھہرا کران کی بات کو ہوا میں اڑاکر بے وزن اور بے حیثیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضرت انعام کو اس پر بھی پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر غازیؒ خلیفہ ا ول کی طبقاتی کشمکش کی پیش بندی کی بات کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں محترم غازی صاحب کے حوالے کو مجبورانہ اعتراف قرار دینے کے فوراً بعد اپنے مضمون ’’اسلامی حکومت کا فلاحی تصور‘‘ کا حوالہ دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اورپھرلکھتے ہیں کہ ’’ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم بھی اس پالیسی سے ملتے جلتے رجحانات رکھتے ہیں۔‘‘
الشریعہ کے صفحہ 442کے نصف آخراور صفحہ443کے نصف اول پر موصوف کے خیالات کو ذرا غور سے پڑھا جائے تو ان کی عقل پر شک سا ہونے لگتا ہے۔سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے پردے میں تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کہ تذلیل کے ساتھ ساتھ محض بھرتی کے لیے کہیں کہیں کچھ روکھے سے اعترافی کلمات بھی لکھ دیتے ہیں۔
اگلے صفحات میں بھی مضمون نگار اپنی پست فطرتی اور گھٹیا ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے طعن و طنز پر مبنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر غازی صاحبؒ پر چٹکیاں لینے کی کوشش کی ہے۔(خاص طور پر صفحہ 446-447)
۷۔ مضمون نگار حضرت انعام کو محترم غازی صاحبؒ پر یہ بھی غصہ ہے کہ وہ مغربی دنیا پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟چنانچہ اس پر وہ بڑے سیخ پا ہوتے ہیں ۔ان کے غصہ اور ناپسندیدگی کا اظہار ان کے ان جملوں سے بخوبی ہوتا ہے:
’’ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم Primogenitureجیسے مغربی قوانین پر تنقید سے اک درجہ بڑھ کر ان کے قوانین کے پس منظر اور مغربی فکر و نظر پر بھی ڈرون حملے کرتے ہیں۔‘‘ (صفحہ453)
’’لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مغربیوں سے خواہمخواہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔‘‘(صفحہ453)
’’ہم یہ کہنے کی جسارت نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر غازیؒ ایسے حقائق سے بالکل بے خبر رہے، البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ انہیں مغربیوں اور مغربی فکر سے خدا واسطے کا بیر لگتا ہے۔‘‘(صفحہ456)
‘‘غالباً ڈاکٹر صاحب ’’فقط اللہ ہو اللہ ہو‘‘ کے قائل ہیں۔‘‘ (ایضاً)
مضمون نگار اپنے مضمون کا اختتام ان جملوں کے ساتھ کرتا ہے:
’’ان محاضرات کے بین السطور ڈاکٹر غازیؒ مغربی فکر سے مخالفت برائے مخالفت کی حد تک الرجک ہیں۔ وہ اپنوں کی خامیوں کے بارے میں گول مول بات کرتے ہیں، لیکن غیروں پر ڈرون حملے کرتے ہیں۔ لیکن اسے اونٹ نگلنے اور مچھر چھاننے سے بھی تعبیر کیاجاسکتا ہے۔‘‘ (صفحہ467)
’’مغربیوں سے خواہ مخواہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں‘‘، ’’مغربی فکر سے مخالفت برائے مخالفت کی حد تک الرجک ہیں‘‘، ’’مغربی فکر سے خدا واسطے کا بیر لگتا ہے‘‘، ’’فقط اللہ ہو اللہ ہو کے قائل ہیں‘‘ ، ’’اونٹ نگلنے اور مچھر چھاننے ‘‘یہ ہیں وہ طنز نما القابات جو مضمون نگار اپنے ممدوح ڈاکٹر غازیؒ کوعطا کرتے ہیں۔طنز اور استہزا کے یہ نشترصرف ایسا شخص ہی محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ پر چلا سکتا ہے جو ان کی ذات، ان کے کردار اور ان کے علمی کام کے بارے میں بدترین حد تک جہالت اور ناواقفیت کا شکار ہو۔بالفاظ دیگر طنز و تعریض کا یہ انداز یا تو بدنیتی کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے یا پھر علم کے فقدان کی وجہ سے۔اور بدقسمتی سے مضمون نگار کے مضمون میں یہ دونوں چیزیں بار بار اپنی جھلک پیش کرتی ہیں۔اس پر مستزاد یہ کہ مضمون نگار بار بار اپنا وزن بڑھانے کے لیے الشریعہ میں اپنے شائع ہونے والے مضامین کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔گویا غازی صاحب ؒ کی تنقیص کے ساتھ ساتھ اپنا مثبت تعارف اور اپنے خود ساختہ علمی کام کا حوالہ دینا بھی نہیں بھولتے۔
ہم دست بستہ عرض کریں گے کہ اگر مضمون نگار اپنے سر سے ’’پروفیسر‘‘ اور ’’میاں‘‘ کی عظیم المرتبت ٹوپیاں اتار کراور انصاف کی آنکھیں کھول کر محترم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار وکردارکا مطالعہ کرتے تو یوں ہجو گوئی اور مغالطہ آمیزی کی غیر اخلاقی حرکات سے محفوظ رہتے۔
ایسا نہ سمجھاجائے کہ ہم ’’تنقیدی کام‘‘ کی افادیت و اہمیت کے خلاف ہیں۔قطعاً نہیں۔ ہم علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ معاشروں اور علمی کام کو درست سمت میں قائم رکھنے کے لیے ’’تنقید‘‘ اور ’’تنقید ی جائزہ‘‘ کی میزان کا قائم رکھنا ایک ناگزیر اور بنیادی ضرورت ہے۔لیکن تنقید اور تنقیص دو مخالف چیزیں ہیں۔ تنقید ایک مقدس فریضہ ہے تو تنقیص اخلاق کی پستی کے اظہار کا نام ہے۔پہلی چیزمعاشروں کو درست سمت میں قائم رکھنے والی، علمی و فکری کاموں کی اصلاح کرنے والی ہے تو دوسری چیز معاشرے کی اخلاقی خوبیوں کی جڑیں کاٹنے والی ہے۔خود ہم نے بھی اپنی ناقص بساط کی حدود میں رہتے ہوئے آج سے قریباً 15سال پہلے اپنے ہی ایک ایسے نہایت محترم راہنما کے کام کا مفصل تنقیدی جائزہ ’’تلاش منزل اور بھٹکتے کارواں‘‘ کے عنوان سے تحریر کرکے اس کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔جسے ہم نے اپنا ’’امیر‘‘ مانا ہوا تھااور حاضر و موجود دینی و مذہبی راہنماؤں میں سے ہم اپنے اس’’امیر‘‘ سے بے حد مرعوب و متاثر بھی تھے۔اور پھر مسلسل چھ سال تک ہم اپنے تنقیدی وتجزیاتی نکات کا دلیل کے ساتھ رد یا قبول کے لیے یاددہانی کراتے رہے اور اپنے تئیں ہمارے مخلصانہ ’’تنقیدی تجزیہ ‘‘ کے جواب میں ہمارے محترم امیر کامسلسل دھتکارآمیزاصراربالآخر اپنی پسندیدہ اسلامی تنظیم سے ہمارے استعفیٰ کا سبب بن گیا۔اتنے طویل اختلاف کے باوجواس امیر کی وفات پر ہم نہایت گہرے دکھ کے احساسات سے دوچار ہوئے،اب اگر ہم ان کی وفات پر ان کے کام اور فکر کے ’’تنقیدی جائزہ‘‘ کے نام سے مضمون لکھ ماریں اور اس میں نہایت کمزور اور بودے دلائل سے ان پر پھبتیاں،طنز اور تعریض کرنے بیٹھ جائیں تو اسے اخلاق کی پستی اورذاتی انتقام تو کہا جاسکتا ہے، ایک علمی و دینی خدمت قطعاً نہیں۔
مضمون نگار سے ہم یہی بات دست بستہ عرض کریں گے کہ ’’تنقید‘‘ اور ’’تنقیدی جائزہ‘‘ کسی بھی فکر و عمل کے معروضی تجزیہ کا نام ہوتا ہے،اور اس معروضی تجزیہ کے بعد اس کام یا فکر کی خوبیوں اور خامیوں کو اسی معروضی انداز میں بیان کرنا ہی تنقیدی جائزہ کہلاتا ہے۔بلادلیل طنز و تعریض اور استہزا کی لٹھ لے کر دوسروں کو ہانکنے کی کوشش کرنا اخلاق سے گرا ہوا کام تو کہلا سکتا ہے ،اسے کسی بھی طرح ’’علم و تنقید‘‘ کی سند عطا نہیں کی جاسکتی۔
ایک طرف مضمون نگار کی یہ تہمتیں، طنز اور خرافات ہیں تودوسری طرف ذرا استاذ محترم ڈاکٹر غازی صاحبؒ کے درج ذیل پرمغز تجزیے کو ملاحظہ فرمائیے اور بتائیے کہ حضرت انعام نے اپنے مضمون میں محترم غازی صاحبؒ پر جو تہمتیں لگائی ہیں کیااس کے وہ سزاوار بھی ہیں؟ غازی صاحبؒ فرماتے ہیں:
’’مغرب اور مشرق دونوں کے تجربات کیا ہیں؟ کیا رہے ہیں؟ علوم کے میدان میں بھی، صنائع اور فنون کے میدان میں بھی، ان سب سے گہری اور ناقدانہ واقفیت دنیائے اسلام کے مستقبل کے لیے ناگزیرہے۔ مغربی تہذیب بہت جامع اور بھرپور تہذیب ہے۔ مغربی تصورات میں کچھ پہلو مفید ہیں، کچھ پہلو ہمارے لیے غیر ضروری ہیں، کچھ پہلو اسلامی شریعت اور عقیدے کی روشنی میں ناقابل قبول ہیں، کچھ پہلو شدید گمراہیوں پر مبنی ہیں۔ .....یہ گمراہیاں قانون اور سیاست کے میدان میں بھی ہیں ۔ معاشیات کے باب میں بھی ہیں، نفسیات اور اخلاقیات سے بھی ان کا تعلق ہے ، معاشرت و معیشت میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔
جب تک ان تمام امور کا الگ الگ جائزہ نہیں لیاجائے گا اور ان گمراہیوں اور غلط تصورات پر عقلی تنقید کرکے ان کا برسرغلط ہونا ثابت نہیں کیاجائے گا، اس وقت تک فکر اسلامی کی تشکیل نو اور فقہ اسلامی کی تدوین نو کا عمل دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں مشکل کام ہے۔ ‘‘ (محاضرات شریعت صفحہ546)
محترم غازی صاحبؒ کا یہ نقطہ نظر ملاحظہ کرنے کے بعدکیا کوئی سنگدل یہ کہہ سکتا ہے کہ ’’ڈاکٹرغازیؒ مغربیوں سے خواہ مخواہ ادھار کھائے بیٹھے تھے‘‘۔ اور یہ کہ ’’وہ مغربی فکر سے مخالفت برائے مخالفت کی حد تک الرجک تھے۔‘‘ قارئین غور فرمائیں کہ کیا ہی اعلیٰ ، خوبصورت اور متوازن تجزیہ ہے استاذ محترم غازی صاحب کا اور کیا ہی گھٹیا اندازِ تہمت ہے ان سنگدل مضمون نگار کا۔
پھر مشرقی و مغربی دنیا کا جو پرمغزتجزیہ محترم غازی صاحبؒ کرتے ہیں اس کا 100واں حصہ بھی مضمون نگار جیسے فکری افلاس کے شکار خودساختہ قلمکاروں کے بس کی بات نہیں۔ملاحظہ فرمائیے صاحب محاضرات فرماتے ہیں:
’’اہل مغرب کے ہاں فکری یک رنگی موجود ہے۔ پورا مغرب ایک خاص رخ پر چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو رویہ فرانس اور پیرس میں محسوس ہوتا ہے وہی رویہ دوسرے مغربی ممالک میں محسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو بات امریکہ میں کہی جارہی ہے وہی اٹلی میں بھی کہی جارہی ہے۔ وہی اسپین میں بھی کہی جارہی ہے۔ ان کے ہاں عزم و ارادہ پایاجاتا ہے اور پچھلے دو سو برس سے دنیائے اسلام کے بارے میں وہ اپنے عزائم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اس معاملہ میں ان کے حکمرانوں اور عامۃ الناس کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تعلیم کی سطح ان کے ہاں اتنی اونچی ہے اور ان کے اپنے مقاصد سے اتنی ہم آہنگ ہے کہ دنیائے اسلام کے ممالک میں اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ان کی معاشی خوشحالی کی بنیاد بڑی مضبوط اور دیرپا ہے۔ وہ خود کفیل ہیں، ان کے پاس بے پناہ عسکری قوت ہے، ان کے ہاں سائنسی تحقیق کے ہزاروں ادارے کائنات کے ذرہ ذرہ اور چپہ چپہ کا سراغ لگارہے ہیں اور تکریم آدم کا تصور ان کے ہاں ایک حقیقت ہے۔‘‘ (محاضرات شریعت صفحہ519)
ہجو گومضمون نگار کو بڑا دکھ ہے کہ ڈاکٹرغازی صاحب ؒ ’’ مغربی فکر و نظر پر ڈرون حملے کرتے ہیں‘‘۔اسی دکھ کی بنیاد پر وہ یہ بے سروپا الزام لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر غازی ’’مغربی فکر سے مخالفت برائے مخالفت کی حد تک الرجک ہیں ‘‘۔لیکن اپنے اس الزام کے ثبوت کے طور پر وہ محترم غازی صاحبؒ کا کوئی حوالہ دینے سے قاصر ہیں ۔جہاں تک ڈرون حملے کرنے کی بات ہے ،توقرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح مضمون نگار نے ڈاکٹرغازی صاحبؒ پر طعنہ زنی کے لیے استعمال کی ہے۔اور ’’ڈرون حملہ‘‘ کا لفظ ایک ’’بے رحم، سنگدل ، ظالم ، بے حس اور یک رخا‘‘ شخصیت کاتاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے ۔کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے مجبور،غریب اور بے قصور مسلمان عوام پر دنیا کا عالمی تھانیدار نہایت سنگدلی ،بے رحمی اور ظالمانہ انداز سے ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملہ آور ہے۔اس اصطلاح کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ’’ڈرون حملہ‘‘ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں بالکل غلطی نہیں کرتا اور بالکل درست اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر اسے تہس نہس کرتا ہے۔اب ذرا اس مفہوم کے پس منظر میں محترم ڈاکٹر غازی صاحبؒ پر ’’مغربی فکر ونظر پر ڈرون حملے ‘‘ کے الزام پر غور فرمایے،اور پھر مضمون نگارکے دکھ اور تکلیف کو سمجھیے کہ ان کو اصل دکھ کیا ہے؟ یہی نا کہ محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی مغربی فکر کا بالکل درست تجزیہ کرکے اس کی گمراہی اور بودا پن بالکل درست انداز میں ثابت کرکے اس کے رعب اور دبدبہ کو تہس نہس کردیتے ہیں اور یوں فکری سطح پر مغربی فکر کا بالکل درست نشانہ لگاتے ہیں۔یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے مضمون نگار کو ہمارے استاد محترم پر غصہ ہے اور یوں وہ غیض و غضب اور بوکھلاہٹ میں’’مغربی فکر پر ڈرون حملے‘‘ کرنے کاواویلا کرنے بیٹھ جاتے ہیں ۔جناب ہجو گو صاحب کے ’’مغربی فکر سے مخالفت برائے مخالفت کی حد تک الرجک‘‘ اور ’’خواہ مخواہ کا بیر‘‘ اور ’’ادھار کھائے بیٹھے ہیں‘‘ جیسے پست ریمارکس کے مقابلے میں محترم غازی صاحبؒ کس خوبصورت انداز سے مغربی فکر کا تجزیہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مضمون نگار جیسے نام نہاد اسلامسٹ(اندر سے مغربسٹ) پر دہشت اور خوف طاری ہوجاتا ہے۔اسی دہشت اور خوف میں وہ ’’مغربی فکر پر ڈرون حملے‘‘ کی رٹ لگانا شروع کردیتے ہیں۔
مغربی فکر و کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے صاحب محاضرات فرماتے ہیں:
’’مغرب کی پوری معیشت دن رات اسی بات کے لیے کوشاں رہتی ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کو نت نئی مادی اور شہوانی خواہشات کی آماج گاہ بنایاجائے۔ ان کی کمپنیاں، ان کی تجارتیں، ان کے بینک، ان کے تجارتی دفاتر، ان کے اشتہارات غرض ہر چیز کا ہدف یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے نئی نئی ضروریات تراشیں۔ پھر لوگو ں کو ان ضروریات کی تکمیل پر آمادہ کریں اور ایسی ایسی چیزیں ان کی بنیادی ضروریات کا حصہ بنادیں جس کے بغیر وہ انتہائی خوشی اور آرام سے زندگی بسر کررہے تھے۔ یہ تصور اسلام کی تعلیم کی رو سے ناقابل قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے بنیادی احکام دراصل اس دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی حقیقی مصلحت کی تکمیل کے لیے دیے گئے ہیں۔ انسان کا حقیقی مفاد اور حقیقی مصلحت کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو شریعت نے بیان کی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کا حصول۔یہ فقہ کے، شریعت کے تمام احکام کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے شریعت کا کوئی پہلو چاہے وہ فقہ المعاملات سے تعلق رکھتا ہو، فقہ مالیات سے تعلق رکھتا ہو، معیشت و تجارت سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ اخروی مقاصد اور اہداف کو سرے سے نظر انداز نہیں کرسکتا۔ اسلامی شریعت اس مغربی تصور کو قبول نہیں کرتی کہ معاشی انسان سے مراد وہ زندہ وجود ہے جس کی زندگی کا مقصد وجود صرف یہ ہو کہ وہ مادی زندگی کا بہتر سے بہتر ہدف اور اعلیٰ سے اعلیٰ سطح حاصل کرے، اور حصول مال، حصول زر اور حصول مادیات کے علاوہ اس کا کوئی محرک نہ ہو۔‘‘ (محاضرات معیشت و تجارت صفحہ92)
’’سرمایہ دارانہ معیشت میں اصل ہدف ہر چیز کی بہتات اور کثرت ہے۔ پیداوار کی بہتات اور maximization، دولت کی بہتات اور maximization، منڈیوں کی وسعت اور بہتات، روزانہ نت نئی ضروریات پیدا کرنا اور غیر ضروری ضروریات کو لوگوں کے لیے ناگزیر بنادینا، یہ مغربی سرمایہ دارانہ معیشت کا ایک اہم پہلو ہے۔ صارفین کی تعداد بڑھانے کے لیے دن رات کوشش جاری رہتی ہے۔ بچتیں بڑھانے کی اہمیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بچتوں کا سود پر چلانا اس پورے عمل کی روح ہے۔ سودی کاروبار کی بہتات اور maximizationدن رات ہورہی ہے۔ پھر سود در سود ادا کرنے کے لیے پیداوار کو مزید بڑھانا ناگزیر ہے۔ جب پیداوار بڑھے گی تو پھر دولت بھی مزید بڑھے گی۔ پھر منڈیوں کی وسعت پیدا ہوگی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سرکل ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ جس کی انتہاء صرف یہ ہے کہ ناجائز ذرائع، ظلم اور اقتدار کی پشت پناہی سے کچھ لوگ اپنی دولت میں لامتناہی اضافہ کرتے چلے جائیں جیسا کہ ہورہا ہے۔ آج مغربی دنیا میں چند سو یا زیادہ سے زیادہ چند ہزار افراد پر مشتمل ایک اقلیتی طبقہ ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔‘‘(ایضاً صفحہ94)
قارئین کرام ! غازی صاحب ؒ کے مغربی نظام پر یہ ہیں وہ ’’ڈرون حملے‘‘جس پر جناب ہجوگومضمون نگار چیں بہ چیں ہیں۔آگے چلیے، صاحب محاضرات فرماتے ہیں:
’’ابھی چند سال پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بڑے مغربی ملک کے چند تیل کے بڑے تاجروں نے پوری دنیا کو ایک شدید افراتفری اور تباہی کا نشانہ بنایا۔ مسلم ممالک کو تباہ و برباد کیا۔ لاکھوں انسانوں کو تہہ تیغ کیا۔ اربوں کھربوں کی جائیدادیں مسلمانوں کی تباہ کردیں۔ ملکوں کے ملک تلپٹ کردیے۔ اس لیے کہ وہ اپنے تجارتی مفاد کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔ ان چند افراد نے اپنے تجارتی مفاد کو محفوظ کرلیا، لیکن اس کی قیمت انسانوں کو کیا ادا کرنی پڑی؟ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس تصور کا جس کی وجہ سے ہر چیز کی بہتات اور کثرت دراصل معیشت کا ہدف ہے۔ یہی maximization اگر حدود سے نکل جائے اور اخلاقی دائرے سے باہر ہوجائے تو اسی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں تکاثر کہاگیا ہے۔‘‘ (ایضاً )
’’مذہبی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے کوئی چیز اچھی ہے یا بری، مغربی معیشت کو اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر انسانوں کی ایک تعداد اس میں دلچسپی رکھتی ہے ، اس پر پیسہ خرچ کرنا چاہتی ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو فراہم کرنا ایک تجارتی اور پیداواری سرگرمی ہے۔ظاہر ہے یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسلامی معاشیات تو دراصل ایک اخلاقی معاشیات ہے، جس میں قسط یعنی حقیقی انصاف پر زور دیاگیاہے۔ اس میں احسان اور ایثار کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ ظاہر ہے احسان اور ایثار خالص مذہبی اقدار ہیں۔ آج کل کے تصورات کی رو سے تجارت کے باب میں ان کو کوئی باریابی حاصل نہیں ہوسکتی۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں تجارت اور اخلاق، تجارت اور مذہبی تصورات ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ پھر شریعت نے جگہ جگہ نصیحت یعنی خیر خواہی کی تعلیم بھی دی ہے۔ خیر خواہی تجارتی رفیق کے لیے بھی ہے، خیر خواہی کسی گاہک کے لیے بھی۔ خیر خواہی ہر انسان کے لیے اور اللہ کی ہر مخلوق کے لیے ہر وقت پیش نظر رکھنا شریعت کی تعلیم کا بنیادی حصہ ہے۔۔۔۔
خلاصہ یہ کہ اسلامی معیشت کا اخلاق اور مذہبی تصورات سے بالکلیہ الگ الگ کردینا شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے برعکس بہت سے مغربی ماہرین معاشیات کا محض خیال ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات ان کے لیے عقیدہ اور یقین کا درجہ رکھتی ہے کہ معاشی ترقی اور مذہبی تصورات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے اپنی تمام معاشی پالیسیاں اور تحقیقات اسی بنیاد پر مرتب و مدون کی ہیں۔ چنانچہ اگر یہ طے کرلیاجائے کہ مذہبی تصورات اور اقتصادی مسائل ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو اس کے نتیجے میں بہت سے سوالات اور مسائل پیدا ہوں گے۔ ربا کے ناگزیر ہونے کا سوال پیدا ہوگا۔ غرر پر اصرار، future salesکی افادیت اور ناگزیر ہونا، کاغذی کرنسی، قرض پر مبنی تجارت اور لین کی تمام صورتیں، یہ سب وہ معاملات ہیں جن کا واحد مقصد دولت کمانا اور دولت میں مسلسل اضافہ کرنا ہے۔ دوسری طرف مذہبی تعلیمات اور اخلاقی اعتبارات کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب امور ناپسندیدہ اور ناقابل قبول قرار پاتے ہیں۔
جدید مغربی معاشیات نے محض اخلاقی یا نظری سوالات ہی نہیں اٹھائے ہیں۔ اس نے محض مذہبی مسائل ہی پیدا نہیں کیے، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں جو خود معاشیات کے اہم مسائل قرار پاتے ہیں۔ اور ان کے حل پر دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں توجہ دی جارہی ہے۔ ان مسائل کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جدید مغربی معاشیات ہی اب سوویت یونین کے زوال کے بعد دنیائے مغرب بلکہ بڑی حد تک پوری دنیا میں اب واحد معاشی نظام ہے۔ اس جدید معاشی نظام میں اصل حیثیت سرمایہ دارانہ تصورات کو حاصل ہے جن کی اٹھان خالص استحصالی ہے۔‘‘(محاضرات معیشت و تجارت صفحہ127-128)
’’یہ عدم توازن جو آج مشرق و مغرب میں پایا جاتا ہے ، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ یہ اس معاشی نظام کے لازمی نتائج ہیں جو آج دنیا میں قائم ہے اور جس کے تحفظ اور دفاع کے لیے مغربی دنیا سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔آج فری مارکیٹ اکانومی اور سرمایہ دارانہ معیشت مغربی دنیا کے لیے دین و ایمان کا درجہ رکھتے ہیں اور مغربی دنیا اس کے لیے اسی طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے جیسا کہ مخلص مسلمان دین کے تحفظ کے لیے قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ بلکہ آج مسلمانوں میں دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کم ہوگیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مغربی دنیا میں اپنے اس نظام کے تحفظ کا احساس دن بدن شدید ہوتا جارہا ہے۔ وہ اس نظام کے تحفظ کے لیے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انسانوں کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ملکوں کے وسائل پر قبضے کے لیے فوجیں اتارنے میں اور بمباری کرنے میں ان کو کوئی تامل نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیاجاسکتا ہے کہ مغربی دنیا اپنے اس نظام کے تحفظ کے لیے کہاں تک جاسکتی ہے۔‘‘ (ایضاً صفحہ134)
’’بے روزگاری ترقی پذیر معیشتوں کا ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ بے روزگاری کھلی بھی ہوتی ہے اور چھپی بھی ہوتی ہے۔ کھلی بے روزگاری تو سب کو نظر آجاتی ہے، لیکن چھپی بے روزگاری بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔یہ کھلی اور چھپی بے روزگاری جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جارہا ہے یہ بھی مغرب کے معاشی نظام کا لازمی تقاضا ہے۔ مغربی ممالک میں آئے دن بڑے پیمانے پر بے روزگاری کی شکایتیں سننے میں آتی ہیں۔ لاکھوں ملازمین کو بڑی بڑی کمپنیاں لے آف کردیتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ان کو اچانک کسی ایسے مالیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑجاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ملازمین کی اتنی بڑی تعداد کا بوجھ نہیں اٹھاسکتیں۔
ایسا اچانک مالیاتی بحران کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کمپنیوں کا سارا کاروبار زرغیر حقیقی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ محض کاغذوں میں قرضے کی رقم بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کاغذوں میں آمدنی اور نفع کی رقم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حقیقی پیداوار یا حقیقی اصول یا موجودات اور اثاثے بہت کم وجود میں آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک غبارے میں گنجائش ہوتی ہے ہوا بھرتی رہتی ہے۔ بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس میں ذرا سا بھی سوراخ ہوجائے تو یہ بہت چھوٹا سا سوراخ اس پوری ہوا کو بہت جلد خارج کردیتا ہے۔‘‘(ایضاً صفحہ136)
مضمون نگار کا الزام ہے کہ صاحب محاضرات ’’اپنوں کے بارے میں گول مول بات کرتے ہیں‘‘۔آئیے، ذرا اس دعوے کا بھی محاضرات معیشت و تجارت کی روشنی میں جائزہ لیتے چلیں:
’’یہ تصوربعض مشرقی ممالک میں اور کچھ مسلم ممالک میں بہت مقبول ہوا۔ کمیونزم تو مسلم ممالک میں زیادہ مقبول نہیں ہوا۔ لیکن سوشلزم کو بعض مسلم حکمرانوں نے بہت پسند کیا۔ کسی معاشی بہبود کی خاطر کم، اقتدار اور استبداد کی خاطر زیادہ۔ انہوں نے دیکھا کہ جن جن ملکوں میں کمیونزم آیا ہے اور وسائل پیداوار پر وہاں ریاست مسلط ہوگئی ہے ان ملکوں میں حکمراں طبقہ کی مخالفت میں کوئی بولنے والا نہیں رہا اور حکمران مطلق العنان اور مستبد ہوگئے ہیں۔یہ منظر بعض مسلمان ڈکٹیٹروں کو بہت پسند آیا اور انہوں نے سوشلزم کے حق میں پروپیگنڈے سے فائدہ اٹھا کر کلی اقتدار اور استبداد کا رویہ اپنایا۔ وسائل پیداوار پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ قوم کی معاشی بہبود کے لیے تو وہ کچھ نہ کرسکے۔ کسی سوشلسٹ مسلم ملک نے اپنے عوام کو وہ عدل و انصاف نہیں دیا۔ وہ وسائل اور سہولتیں فراہم نہیں کیں جن کی فراہمی کا دعویٰ کرکے وہ اقتدار پر قابض ہوئے تھے۔ ہاں استبداد اور ڈکٹیٹرشپ کے ایک سے ایک بڑھ کر نمونے ان مسلم ممالک میں سامنے آئے جہاں سوشلزم کے نام پر کچھ افراد اقتدار پر قابض ہوئے۔‘‘(ایضاً صفحہ95)
’’پاکستان میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔بعض ایسے ذمیندار جن کو انگریزوں نے سینکڑوں، ہزاروں ایکڑ کے حساب سے زمینیں دے دی تھیں۔ آج وہ زمینیں ان میں سے بعض کے خاندانوں کے پاس موجود ہیں۔ لیکن وہ ان کو خود آباد نہیں کرسکتے، کسی کو دینا بھی نہیں چاہتے۔ حکومتوں نے ان سے یہ زمینیں واپس لینے میں کوتاہی کی۔ مختلف سیاسی اور غیر سیاسی مفادات کی وجہ سے اس طبقے کو مزید نوازا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی وہ زرعی اراضی جو پاکستان کی موجودہ آبادی سے کئی گنا آبادی کے لیے کافی ہے اور ذرا سی توجہ سے اس سے زیادہ کے لیے بھی کافی ہوسکتی ہے وہ موجودہ آبادی کے لیے بھی بعض اوقات کافی نہیں ثابت ہوتی اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ پیداوار میں کمی آجاتی ہے۔ اور بعض بہت اہم زرعی اجناس کی پیداوار بیرون ملک سے منگوانی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ذرائع پیداوار کا استعمال نامکمل ہے اور وسائل کی تقسیم غیرعادلانہ ہے۔‘‘(ایضاً صفحہ 132)
’’مزید برآں ہمارے ملک میں خاص طور پر جاگیرداری کا نظام اس غیر منصفانہ تقسیم دولت اور غیر عادلانہ تقسیم وسائل کو پختہ سے پختہ تر کرنے کا سبب بنا ہے۔ سرمایہ داروں یا جاگیرداروں کے بعض ممالک میں الگ الگ طبقے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بیشتر صورتوں میں یہ دونوں ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے وافادر سرداروں اور بااثر لوگوں کو زمینیں دے کر زمینداروں کا ایک طبقہ پیدا کیا۔ اس زمیندار طبقے نے ملک کے زرعی وسائل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر ان زرعی وسائل سے کام لے کر صنعتیں قائم کیں۔ ان صنعتوں سے کام لے کر بڑی بڑی تجارتیں اپنے کنٹرول میں کیں۔یوں ملک کے بڑے بڑے تجارتی ادارے ان کے انتظام میں آگئے۔ اس معاشی قوت سے کام لے کر انہوں نے سیاسی قوت بھی حاصل کرلی۔ اس طبقے کے بہت سے لوگ سول بیوروکریسی میں بھی شامل ہوئے اور اب صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ طبقہ جس کو انگریز نے اپنے استعماری مفادات کی خاطر وسائل سے نوازا تھا، جس کی بدولت چار ہزار انگریز پورے برصغیر پر حکومت کرتے رہے۔ وہ طبقہ اب پاکستان کا مستقل طور پر مالک بن چکا ہے۔ وہ طبقہ اب پاکستان کا مستقل طور پر حاکم بھی بن گیا ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے میں جو انگریز متعین تھے ان کی تعداد چار پانچ سو سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ چار پانچ سو انگریز جوساڑھے تین لاکھ مربع میل پر حاکم تھے، اسوقت تین ساڑھے تین کروڑ آبادی کو کنٹرول کررہے تھے۔ وہ اسی وفادار اور جاگیردار طبقہ کے زور پر کررہے تھے۔‘‘(ایضاًص141)
کیا ہجوگوصاحب بتاسکتے ہیں کہ ان سطور میں غازی صاحب ؒ نے اپنوں کے بارے میں جوتجزیہ کیا ہے، وہ ’’گول مول‘‘ ہے۔ استاذ محترم ان اہل علم میں سے تھے جنہیں مائیں صدیوں بعد پیدا کرتی ہیں۔اپنے ہوں یا پرائے، ان کی رائے اور تجزیہ بے لاگ، غیر جانبدارانہ، مثبت ، تعمیری اور گہرے و پختہ علم و فکر اور تجربے کا حامل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر محترم غازی صاحب ’’اپنوں‘‘ کے بارے میں ایسی ہی بے لاگ اور معروضی رائے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:
’’اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ دنیائے اسلام کا کوئی واضح نصب العین اور کوئی متعین ہدف نہیں ہے۔ عامۃ الناس کے عزائم اور خواہشات میں جو ہرجگہ یکساں ہیں اور حکمرانوں کے عزائم اور خیالات میں کوئی توافق اور ہم آہنگی نہیں۔ عامۃ الناس کی خواہشات، آرزوئیں اور امیدیں انڈونیشیا سے مراکش تک ایک جیسی ہیں۔ لیکن حکومتوں کا ، سیاسی قیادتوں کا اور فکری اور سرکاری سیاسی اور اقتصادی راہنماؤں کا کوئی ہدف نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فکری الجھنیں عام ہیں۔ کوئی عزم و ارادہ کسی سطح پر موجود نہیں ہے۔ آپس میں بدترین اختلافات ہیں، تعلیم کی سطح بہت پست ہے، معاشی بنیادیں کمزور ہیں۔ دنیائے اسلام میں جو ممالک بہت خوشحال نظر آتے ہیں، ان کی خوشحالی کی بنیاد بھی کوئی مضبوط اور دیرپا نہیں ہے۔ بہت سی صورتوں میں یہ ظاہری خوشحالی ہے اور بعض بااثر مغربی طاقتوں کی مبنی برمصلحت سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ اس خوشحالی کا کنٹرول اور سوئچ مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ سوئچ آف کردیاجائے تو ساری معاشی چکاچوند آن واحد میں ختم ہوجائے گی۔ مسلم ممالک کا دوسروں پر انحصار ہے، اکثر مسلم ممالک عسکری اور سائنسی طور پر کمزور ہیں۔ بے توقیری آدم کے نمونے ہر مسلم ممالک میں کثرت سے نظر آتے ہیں۔ یہ فرق اس وقت ہمارے اور دنیائے مغرب کے درمیان قائم ہے۔ ان حالات میں کیا دنیائے اسلام اور دنیائے مغرب میں مقابلہ برابر کا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے۔‘‘(محاضرات شریعت صفحہ 519۔520)
نہایت متوازن فکر و عمل کے حامل ،علم و فکر کی بلندیوں کو چھونے والے ایک نہایت محترم استاد کی وفات کے موقع پر مضمون نگار کی طرف سے کی جانے والی ہجو گوئی اور فکری کجی پر ہمارے لیے خاموش ہونا ناممکن ہوگیاتھا۔ہمیں افسوس ہے کہ مضمون نگار کے جملوں کی ترتیب ،الفاظ و اصطلاحات کے استعمال اور فکری تجزیے کے مطالعے کے نتیجے میں ہم ان کے بارے میں وہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوئے جس کا اظہار سابقہ سطور میں بہ تکرار ہوا ہے۔
مکاتیب
ادارہ
(۱)
(ماہنامہ ’’الحامد‘‘ لاہور کے مارچ ۲۰۱۱ء کے شمارے میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ کا ایک مضمون شائع ہوا تھا جسے ’’الحامد ‘‘ کے شکریے کے ساتھ الشریعہ کے جون ۲۰۱۱ء کے شمارے میں ’’توہین رسالت کے مرتکب کے لیے توبہ کی گنجائش‘‘ کے عنوان سے نقل کر دیا گیا تھا۔ تحریر کا اصل ماخذ اسلامی نظریاتی کونسل کی سالانہ رپورٹ ۲۰۰۳-۲۰۰۴ء ہے جو کونسل کی طرف سے سرکاری طور پر طبع شدہ ہے۔ اس ضمن میں دار العلوم کراچی کے دار الافتاء کی طرف سے ہمیں درج ذیل وضاحتی موصول ہوا ہے جسے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مدیر)
مکرمی جناب مدیر ماہنامہ ’’الشریعہ‘‘
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید ہے مزاج گرامی بخیریت ہوں گے۔ گزارش ہے کہ ماہنامہ ’’الشریعہ‘‘ کے جون کے شمارہ میں شامل صفحہ نمبر ۱۸ پر ایک مضمون جو ماہنامہ ’’الحامد‘‘ کے شکریے کے ساتھ حضرت صدر جامعہ دار العلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیۃ کی جانب منسوب کر کے شائع کیا گیا، جس کا عنوان ہے ’’توہین رسالت کے مرتکب کے لیے توبہ کی گنجائش‘‘، حضرت نے یہ مضمون ملاحظہ فرمایا ہے اور اس پر تشویش کا اظہار فرمایا ہے کہ انھیں ایسا کوئی مضمون تحریر کرنا یاد نہیں، دوسرا یہ کہ بلااجازت شائع کیا گیا اور کسی کا مضمون بلا اجازت شائع کرنا مناسب نہیں، بالخصوص جبکہ مضمون علمی اور فقہی ہو۔ تیسرا یہ کہ اس مضمون میں غلطیاں بھی ہیں جس سے پڑھنے والا غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اس بارے میں آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ شمارے میں اس بات کی واضح تردید کر دی جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ یہ مضمون غلطی سے حضرت کے نام سے شائع کیا گیا ہے اور حضرت کو اس مضمون سے مکمل طور پر اتفاق بھی نہیں ہے۔ مدیر ماہنامہ ’’الحامد‘‘ کو بھی اطلاع کے لیے خط بھیجا جا رہا ہے۔ والسلام
عبد الرؤف سکھروی
ناظم دار الافتاء، جامعہ دار العلوم کراچی
۲۰ رجب ۱۴۳۲ھ/۲۳ جون ۲۰۱۱ء
(۲)
محترمی عمار خان ناصر صاحب
آداب! ماہنامہ ’الشریعہ‘ شمارہ جولائی ۲۰۱۱ء موصول ہوا۔ کرم فرمائی کے لیے ممنون ہوں۔
فہرست عناوین ہی کہہ رہی ہے کہ یہ شمارہ روشن فکری اور وسیع النظری کا مرقع ہے۔ ایسے موضوعات پر مکالمے کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، تاہم ناانصافی ہوگی اگر اس شمارہ کے ’’حاصل غزل‘‘ مقالہ بہ عنوان ’’سماجی، ثقافتی، سیاسی دباؤ اور دین کی غلط تعبیریں‘‘ از حافظ محمد صفوان کی تعریف نہ کروں۔ ادبی ولسانی موضوعات پر تو موصوف کی تحریریں ہند و پاکستان کے تقریباً تمام موقر جرائد میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس شگفتہ انداز میں دین کی غلط تعبیروں پر جامع اظہار خی ال انھی کا خاصہ ہے۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہے تو بہت اچھا ہوگا۔
مستشرقین کی علمی خدمات بیسویں صدی کے دینی لٹریچر کا اہم پہلو ہے، لیکن اس پر کماحقہ کام نہیں ہوا۔ بعض اہم موضوعات پر مستشرقین کے مقالات پرانے جرائد مثلاً اسلامک ریویو، اسلامک کلچر وغیرہ میں مل جاتے ہیں۔ دور حاضر کے بعض مسائل کی تفہیم وتشریح کے لیے اور ان پر مثبت بحث کے آغاز کے لیے ان مقالات کا ترجمہ کروا کر بھی شامل اشاعت کیجیے۔
والسلام
محمد اطہر مسعود، لاہور
۱۳؍ جولائی ۲۰۱۱ء
(۳)
Brother Ammar
I happened to see the letter against my article on Science by brother Izhar. Let me be blunt to say that I was not shocked at all on reading his letter asserting that it is not possible to biffercate knowledge on capitalist and non-capitalist grounds. So is the case because I know that science is the diety of modern man who believes in it even without understanding what it actually is. Most of them jump in to defend it without studying basic issues of philosophy of science, theory of knowledge etc. However, I am sometimes really surprised at the fact that Muslims are keen to defend that western heritage (which is infact a social filth) which west has condemned itself. I will be happy to see if my brother could come up with some concrete and well referenced criticism on my article, instead of thrashing me with baseless and rhetorical labels.
Zahid Mughal
سیمینار: ’’پر امن اور متوازن معاشرے کے قیام میں علماء کا کردار‘‘
ادارہ
(پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے زیر اہتمام قومی سیمینار)
۲۱ تا ۲۳ جون ۲۰۰۱ء کو پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز، اسلام آباد کے زیر اہتمام اسلام آباد ہوٹل، اسلام آباد میں ’’ پُرامن اور متوازن معاشرے کے قیام میں علماء کا کردار‘‘ کے عنوان پر دو روزہ قومی سیمینار منعقد ہوا جس میں تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام نے شرکت کی اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علمائے کرام نے پاکستان میں پُرامن اور متوازن معاشرے کے قیام کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور اس اَمر پر زور دیا کہ اختلافِ رائے کو لوگوں کے درمیان نفرت کو فروغ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔انہوں نے اتفاق کیا کہ معاشرے میں پنپنے والے ہر طرح کے پُرتشدد رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے سیمینار کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بہت سارے مسائل غیر آئینی اور غیر جمہوری ادوار میں فروغ پائے ہیں، اور یہی اَمر معاشرے میں امن اور رواداری کی موجودہ ناگفتہ بہ صورتحال کے پسِ پردہ کارفرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت بُری حکمرانی اور معاشرے کی سمت کا تعین نہ ہونے کے باعث فروغ پا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ علمائے کرام بھی اپنا اصلاحی کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دلیل اور جواز کی جگہ فتوے نے لے لی ہے اور قانون کی حکمرانی پر بندوق کی حکمرانی غالب آگئی ہے۔ انہوں نے اس اَمر پر زور دیا کہ علمائے کرام کو امن اور محبت کے پیغام کو فروغ دینا چاہیے اور ذاتی محاسبہ ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
پاک انسٹی ٹیوٹ فار پیس سٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا نے کہا کہ پاکستان میں امن و رواداری کے فروغ میں علمائے کرام کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر اُس وقت جب شدت پسنداور پرتشدد رجحانات کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور لوگ ان کی حقیقی وجوہات سے آگاہ نہیں ہے ۔
سیمینار کی پہلی نشست بعنوان ’’ پرامن اور متوازن معاشرے کے خدوخال‘‘ سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر علماء اکادمی، منصورہ ڈاکٹر فرید پراچہ نے موضوع کا علاقائی اور عالمی تناظر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان حالتِ جنگ میں ہے اور علماء کرام لوگوں کے درمیان انسانی زندگی کے تقدس کو اجاگر کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔جامعۃ المنتظرسے وابستہ مذہبی سکالر ڈاکٹر سید محمد نجفی نے پُرامن اور متوازن معاشرے کے سماجی و ثقافتی عوامل پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ایسے معاشرے کے قیام لیے یکساں مواقع پیدا کرنے اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔انہوں نے انسانی حقوق کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
فرقہ ورانہ ہم آہنگی پر گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل دارالعلوم گلگت مولانا عطاء اللہ شہاب نے کہاکہ پُرامن معاشرے کے قیام کے لیے مذہبی اور سیاسی رواداری انتہائی اہم ہے، تاہم پاکستان میں ان دونوں کا وجود نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال تھاکہ مذہبی عدم رواداری اور فرقہ واریت مذہب بیزار رویوں کے فروغ کا باعث بنتی ہے۔
معروف مذہبی سکالر ڈاکٹر خالد ظہیر نے کہا کہ فرقہ واریت کے تدارک کے لئے یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے لیے امام کا تقرر کرے اور خطبے کے متن کی تحریر کا اہتمام بھی کرے۔ پہلی نشست کی صدارت جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ مولانا حنیف جالندھر ی نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ سماجی استحصال کے خاتمے اور فوری اور بروقت انصاف کی فراہمی سے معاشرے میں امن اور رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔
سیمینار کی دوسری نشست بعنوان ’’ پُرامن اور متوازن معاشرے میں درپیش چیلنجز‘‘ سے خطاب کرتے ہوئے جامعہ نعیمیہ ، لاہور کے مہتمم مولانا راغب نعیمی نے کہا کہ تعلیمی مواقع کی کمی اور سماجی تقریق کے باعث معاشرے میں انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی عدم مساوات اور غربت کے باعث معاشرے میں عسکریت پسندی کو فروغ حاصل ہو رہا ہے ۔ متوازن معاشرے کے قیام کے لیے سماجی شعبے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
پشاوریونیورسٹی کے سنٹر فار اسلامک سٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر قبلہ ایاز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان جہاد کے باعث صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاق کے زیرِانتظام قبائلی علاقوں میں مذہبی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کو فروغ حاصل ہوا جس نے ان علاقوں میں سماجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا جبکہ فرقہ واریت بھی تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن کے قیام اور رواداری کے فروغ میں علمائے کرام اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔
رابطۃ المدارس کے رہنما اور جامعۃ الفلاح کے پرنسپل قاری ضمیر اختر منصوری نے کہا کہ سندھ میں لسانی، فرقہ وارنہ تشدد اور مجرمانہ کارروائیاں سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ کراچی اور اندرونِ سندھ میں حکومت کی رٹ نہ ہونے کے باعث صوبے میں امن وا مان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔وفاق المدارس شیعہ، بلوچستان کے نمائندے علامہ اکبر حسین زاہدی نے کہا کہ بلوچستان میں شورش ہماری اپنی پالیسیوں کے باعث شروع ہوئی ہے جس کے لیے ہمیں ملکر کام کرنا چاہیے۔ جامعہ اسلامیہ مظفرآباد کے مہتمم قاضی محمود الحسن اشرف نے کہا کہ مساجد اور مدارس کے نظام کی تنظیمِ نو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں علم کے گہوارے بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ اختلافِ رائے ایک صحت مند اور متنوع معاشرے کی علامت ہے۔
دوسری نشست کی صدارت کرتے ہوئے مہناج القرآن علماء کونسل کے سربراہ علامہ سید فرحت حسین شاہ نے کہا کہ معاشرے میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے مذہبی عقائد اور شعائرات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان حالات میں یہ علمائے کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہر سطح پر ان مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
سیمینار کی تیسری نشست بعنوان ’’ پُرامن اور متوازن معاشرے کے قیام میں علماء کا کردار‘‘ سے خطاب کرتے ہوئے وفاق المدارس سلفیہ کے سربراہ مولانا یٰسین ظفر نے کہا کہ علمائے کرام کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں پنپنے والی مذہبی عدم رواداری، عسکریت پسندی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ کے وائس پرنسپل ڈاکٹر ابوالحسن شاہ نے کہا کہ دوسرے مکاتبِ فکر ، ان کے رہنماؤں اور عقائد کا احترام مختلف مسالک کے درمیان کشیدگی کو کم کر سکتا ہے۔ سابق سینیٹر اور مدرسہ عارف الحسینی پشاور کے مہتمم علامہ جواد ہادی نے کہا کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ علماء معاشرے میں بد امنی کے ذمہ دار ہیں۔چنانچہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں امن اوررواداری کے فروغ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں۔ وائس پرنسپل الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ مولانا عمار خان ناصر نے کہا کہ عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے علماء کرام قومی ایشوز جیسا کہ افغانستان اور کشمیر میں جہاد اور خروج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل طے کریں۔
اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق سربراہ ڈاکٹر خالد مسعود نے قانون کی حکمرانی قائم کرنے پر زور دیا اور کہا کہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ اختتامی نشست سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر برائے انسانی حقوق مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کی طرز پر اسلامی ممالک کی یونین قائم کی جانی چاہیے۔
رؤیت ہلال کمیٹی اور تنظیم المدارس کے سربراہ مولانا مفتی منیب الرحمٰن نے آخری نشست کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی ہر کوتاہی کی ذمہ داری دوسروں پر عائد نہیں کرسکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ذاتی محاسبے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس اَمر پر زور دیا کہ دہشت گردی کے لیے کسی بھی قسم کا جواز نہ تراشا جائے اور حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے واضح پالیسی اختیار کرے۔ ڈائریکٹر پاک انسٹی ٹیوٹ فار پیس سٹڈیز محمد عامر رانا نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ عالمگیریت کے موجودہ دور میں مکالمہ سب سے پُراثر ہتھیار ہے۔ انہوں نے گفتگو میں اٹھائے گئے نکات کو سراہا اور کہا کہ عہدِ حاضر کے مسائل اور چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس نوعیت کی گفتگو کے ذریعے حل کی جانب بڑھا جا سکتا ہے
سیمینار کے دوران معاشرے میں امن اور رواداری کے فروغ پر گفتگو کرنے اور سفارشات کی تشکیل کے لیے پانچ مشاورتی گروپ تشکیل دیے گئے۔ ان مشاورتی گروپوں نے پانچ مختلف موضوعات پر گفتگو اور مشاورت کی:
(1) معاشرے میں متوازن فکر کے فروغ میں مدارس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
(2) معاشرے میں امن اور رواداری کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟
(3) سیاسی رویوں اور سماجی و ثقافتی انتہا پسندی کے رَد کے لیے تجاویز۔
(4) معاشرے سے انتہا پسندی کے خاتمہ کے لیے علماء کا کردار۔
(5) معاشرے میں فرقہ ورانہ ہم آہنگی کے لیے علما ء کا کردار۔
طویل مشاورت کے بعد یہ مشاورتی گروپ معاشرے میں امن اور رواداری کے قیام کے لیے کچھ سفارشات پر متفق ہوئے اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سفارشات پرامن اور متوازن معاشرے کے قیام کا سبب بن سکتی ہیں۔
پہلے گروپ نے ’’ فرقہ واریت کے خاتمے میں علماء کا کردار‘‘ کے موضوع پر سفارشات پیش کیں۔ اس گروپ میں منتظم بحث سید فرحت حسین شاہ جبکہ محرکِ بحث مولانا عبدالاکبر چترالی تھے، جبکہ شرکا میں مولانا مسعود بیگ، علامہ اکبر حسین زاہدی، مولانا عبدالقدوس محمدی اور مولانا عطاء اللہ شہاب شامل تھے۔ سفارشات یہ ہیں:
(1) جملہ مکاتب فکر کے مابین ’مشترکات‘ کو فروغ دیا جائے۔
(2) جملہ مکاتب فکر جہلا کو اپنی اپنی مساجد کے منبر و محراب تک پہنچنے سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔
(3) فرقہ واریت کے اسباب کا سدِباب کیا جائے۔
الف۔ دل آزار تحریروں اور تقریروں پر پابندی عائد کی جائے۔
ب۔ فتویٰ نما نعروں سے تمام علماء اپنے اپنے پیروکاروں کو روکیں۔
ج۔ عالمی استعمار کی سازشوں سے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔
(4) اختلافات کے ہوتے ہوئے باہمی احترام اور برداشت کو فروغ دیا جائے۔
(5) تمام مکاتب فکر کے عقائد پر مشتمل، ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں ہر مسلک کا عقیدہ خود انہی کے جید علماء کرام پیش کریں۔
(6) فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے قرآن و سنت کو محور و مرکز بنایا جائے۔أ) لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو محدود کرتے ہوئے اسے ضابطہ اخلاق کے تحت کیا جائے۔
(8) ملکی سطح پر ایک ایسا فورم تشکیل دیاجائے جو تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور مفتیان عظام پر مشتمل ہو اور فتویٰ جاری کرنے کا اختیار اسی فورم کے پاس ہو۔
(9) ایسی سرگرمیاں جن سے باہمی تعلقات کو فروغ ملے، ان کا اہتمام ہو اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت کا اہتمام کیا جائے۔
(10) مختلف مسالک نے موضوعات کی جو تقسیم و تفریق کر لی ہے، وہ ختم کی جائے۔ محرم اور ربیع الاول سمیت دیگر مواقع پر تمام مکاتب فکر کے علما شریک ہوں۔
(11) مذہبی ہم آہنگی اور باہمی روابط و مکالمہ کا عمل دینی مدارس کے طلبہ کی سطح سے شروع کیا جائے۔
(12) دینی مدارس، جامعات اور مساجد کے نام عمومی اور قابلِ قبول ہونے چاہئیں جو مسلکی اختلافات کا تاثر نہ دیتے ہوں۔
(13) ہر مکتبۂ فکر میں جو چند گنے چنے لوگ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، ان کا محاسبہ کیا جائے۔
(14) توہین آمیز، اشتعال انگیز اور کفر و ارتداد کے فتاویٰ پر مشتمل لٹریچر اور مواد کو ضبط کیا جائے۔
(15) علماء کرام دین کی تبلیغ کو مقدم رکھیں، مسلک کے پرچار کو ترجیح نہ دیں۔
(16) ذرائع ابلاغ کو پابند کیا جائے کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے پروگرام اور مواد نشر نہ کریں۔
(17) ملکی سا لمیت اور امن و امان کو پیشِ نظر رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔
(18) فرقہ واریت کے نقصانات، خطرات اور تباہ کاریوں کی تقریری اور تحریری صورت میں نشاندہی کی جائے۔
دوسرے گروپ منتظمِ بحث خورشید احمد ندیم اور محرکِ بحث مولانا مفتی محمد زاہد تھے۔ شرکا میں پیرسید مدثر شاہ، مولانا فضل الرحمان مدنی، ڈاکٹر خالد مسعود، علامہ محمد حیات قادری اور علامہ انیس الحسنین خان شامل تھے۔ اس گروپ نے ’’پرتشدد رجحانات کے خاتمے میں علماء کا کردار‘‘ کے عنوان پر اپنی سفارشات مرتب کیں۔ اس گروپ کی رائے میں معاشرے کو تشدد سے پاک کرنے کے لیے علماء کو درج ذیل تین دائروں میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے:
1: ریاستی امور
1.1: سیاست میں علماء کے کردار کے تعین کے لیے برصغیر کی تاریخ میں علماء کے سیاسی کردار کی تفہیم نو کی جائے۔
1.2: جدید ریاست اور اس کے اداروں سے علماء کو متعارف کروانے کا اہتمام کیا جائے۔
1.3: ریاستی امور میں اصلاح کے لیے پرامن ذرائع اختیار کیے جائیں۔
1.4: علماء او ردیگر طبقات کے درمیان موجود بعد کو دور کیا جائے۔
II: سماجی امور
1: اصلاحِ معاشرہ کے لیے دین کی روحانی تعلیمات اور ان سے متعلق اداروں کا احیاء اور اصلاح کی جائے۔
2: سماجی اصلاح کے لیے محراب و منبر کو مزید فعال اور مؤثر بنایا جائے۔
III: دینی امور
3.1: دین کے فہم اور تشریح کے لیے معتبر اور جید علماء سے ہی رجوع کیا جائے۔
3.2: علماء ، دینی اداروں اور تنظیموں میں بھی خوداحتسابی کو رواج دیا جائے۔
3.3: مسلکی ہم آہنگی کے لیے دوسرے مسالک کا مبنی بر انصاف تعارف شامل نصاب کیا جائے۔
3.4: مختلف مسالک کے اعلیٰ سطح کے علما کے روابط کو نچلی سطح تک فروغ دیاجائے۔
3.5: فتویٰ دیتے وقت شرعی، اخلاقی اور سماجی اصولوں کو مدنظر رکھا جائے۔
3.6: دینی مدارس اور عالمی دینی یونیورسٹیوں میں تعاون اور رابطے میں اضافہ کیا جائے۔
3.7: تکفیر، خروج اور دیگر مسائل میں رائے دینے کے لیے تمام مسالک کے جید علماء اور اسکالرز پر مشتمل ایک فورم بنایا جائے۔
تیسرے گروپ کی سفارشات کا عنوان ’’بدامنی اور عدم توازن کے سیاسی، سماجی اور معاشی محرکات اور تدارک‘‘ تھا۔ اس گروپ کے منتظمِ بحث ڈاکٹر عبدالناصر لطیف اور محرکِ بحث مولانا مفتی محمد رفیق بالاکوٹی تھے، جبکہ شرکا میں قاری ضمیر اختر منصوری، مولانا علی بخش سجادی، مولانا محمد یونس قاسمی اور مولانا خالد ضیاء شامل تھے۔ اس گروپ نے حسب ذیل سفارشات پیش کیں:
سیاسی محرکات :
(1) جمہوری نظام سیاست میں عدمِ برداشت ، سیاست دانوں کی نااہلی اور قیادت کے فقدان کے باعث مسائل کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں حکمران طبقے کو اپنی ترجیحات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں سماجی اور معاشی انصاف کے حصول کو ممکن بنایا جاسکے۔
(2) سیاست دانوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے عوام کو استعمال کرنے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
(3) پاکستانی طرزِ حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔
(4) ریاست اور حکمرانوں کو بیرونی طاقتوں کا آلہ کار بننے کے بجائے قومی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے۔
(5) پاکستان کا سیاسی نظام دغا بازی، مکاری اور منافقت پر مبنی ہے۔سیاسی اور جمہوری نظام کی درستگی کے لیے مدبر قیادت کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔
(6) سیاسی نظام کی درستگی کے لیے علماء کے عملی کردار کی ضرورت ہے۔
سماجی محرکات:
(1) عوام کی ناخواندگی، جہالت اور تعلیم سے دوری کے اسباب حکمران اور وڈیرہ شاہی ہے۔حکومتی سطح پر معیاری تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
(2) مختلف نظامِ ہائے تعلیم کی پیداوار، مختلف اذہان کی صورت میں جنم لیتی ہے، اور یہی ذہنی اختلاف معاشرے میں عدم توازن کا سبب بنتا ہے۔ایک متوازن تعلیمی نظام، جس سے ایک فکر کے لوگ پیدا ہوں، معاشرے میں امن کا سبب بن سکتاہے۔
(3) حکمران طبقہ ملک میں امن و امان کے فروغ کے لیے علماء کرام اور مذہبی اسکالرز کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرے۔
(4) عدمِ مساوات، طبقاتی تقسیم، احساسِ برتری، علماء کی کردارکشی، حکمرانوں کی سرپرستی میں جرائم کا فروغ، اتحاد و اتفاق کا فقدان، عصبیت، لسانیت اور اختلاف برائے محاصمت کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔
(5) عدلیہ، انتظامیہ اور میڈیا کا کردار مثبت ہونا چاہیے۔
(6) تطہیر افکار کا نہ ہونا اور فقدان تزکیہ ، ذمہ داریوں کا تعین اور احساسِ ذمہ داری کا نہ ہونا، ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر قربان کرنا، اسلام کے عائلی نظام کی تباہی، ظلم کے مقابلے میں عدم تعاون، عفو و درگزر اور برداشت کی کمی جیسے عوامل غیرمتوازن رویوں کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں، جن سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔
معاشی محرکات:
(1) جاگیرداری نظام ایک ناسور کی طرح ہے جس کا شرعی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
(2) معاشی عدمِ مساوات اور دولت کی غیرمنصفانہ تقسیم کو ختم کیا جانے چاہیے۔
(3) سستی اور کاہلی کے باعث محنت و عمل کے ذریعے ذرائع آمدن کا حصول کم ہوتا جا رہا ہے۔محنت کے بغیر حاصل ہونے والے منافع اور ذرائع آمدن کی روک تھام کی جانی چاہئے۔
(4) اسلام کے اصولِ انفاق (صدقہ و زکوۃ) کے فرضی و نفلی احکامات سے لاپرواہی کی جاتی ہے۔اسلام نے واضح طور پر صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں، ان پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔
(5) سودی نظام اور سرمایہ دارانہ کلچر معاشرے میں بگاڑ پیدا کررہا ہے جس کا تدارک فوری طور پر ہونا چاہیے۔
(6) بجلی کی پیداوار ، انڈسٹری کا استحکام، زراعت کی پیداوار، فنی مکاسب کی بہتر تنظیم اور ملکی ذخائر کا بہترین استعمال ملک میں معاشی استحکام کے لیے بہترین ثابت ہوسکتا ہے۔
(7) بیرونی امداد اور غیرملکی قرضوں کا حصول کم سے کم کیا جائے اور ملک کے اندر ذرائع آمدن پیدا کیے جائیں۔
چوتھے گروپ کے منتظمِ بحث مولانا بابر حسین بابر اور محرکِ بحث مولانا محمد عمار خان ناصر تھے، جبکہ شرکا میں مولانا یٰسین ظفر، مولانا عبدالحق ہاشمی، مولانا ممتاز نظامی، علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی، مولانا اصغر عسکری اور مولانا عبدالسلام شامل تھے۔ اس گروپ نے ’’برداشت کے کلچر کا فروغ کیسے ہو؟‘‘ کے زیر عنوان اپنی سفارشات مرتب کیں جو حسب ذیل ہیں:
1۔ برداشت کے کلچر کے فروغ کے لیے افراد معاشرہ کی تربیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کا آغاز گھر کے ماحول سے ہونا چاہیے اور بچوں کو اس کی عملی تربیت دی جانی چاہیے تاکہ وہ ناپسندیدہ صورت حال میں اپنے رد عمل کو منفی ہونے سے بچا سکیں۔
2۔ افراد میں متوازن شخصیت کی تعمیر کو تعلیمی نصاب، ذرائع ابلاغ کے پروگراموں، مذہبی خطبات ودروس اور تربیتی ورک شاپس کا باقاعدہ موضوع بنایا جائے۔
3۔ دینی مدارس اور جدید تعلیمی اداروں کے نصابات میں ایسا مواد شامل کیا جائے جس کا مقصد مختلف فکری دھاروں کا مثبت تعارف حاصل کرنا ہو اور جس سے دوسرے طبقات کے انداز فکر کو دیانت داری اور رواداری کے ساتھ سمجھنے کا رویہ پیدا ہو۔
4۔ علما وخطبا دعوت وتبلیغ میں مسلکی پہلو کو غالب کرنے کے بجائے مشترکہ دینی تعلیمات اور اخلاقیات پر توجہ مرکوز کریں تاکہ سامعین میں افتراق وانتشار کے بجائے اتحاد کے جذبات پیدا ہوں۔
5۔ اس بات کو بطور ایک مسلمہ اصول اور قدر کے فروغ دیا جائے کہ ہر طبقے کو اپنے فہم کے مطابق عقیدہ اور رائے رکھنے اور اسے مثبت طو رپر بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ نیز یہ کہ کسی بھی طبقے کے نظریات اور عقائد کی وہی تشریح مستند اور قابل قبول ہے جسے وہ خود بیان کرتا ہو۔
6۔ جن امور میں (چاہے وہ مذہبی واعتقادی ہوں یا فکری وسیاسی وسماجی) اختلاف رائے پایا جاتا ہے، ان میں مخالف نقطۂ نظر پر تنقید کرتے ہوئے علمی رویے کو فروغ دیا جائے۔ اہل علم کے مابین ایسی بحثوں پر علمی رنگ غالب ہونا چاہیے، جبکہ عوامی سطح پر اظہار خیال کرتے ہوئے تنقید کے انداز سے ہمدردی اور خیر خواہی کی جھلک دکھائی دینی چاہیے۔
7۔ مختلف طبقہ ہاے فکر کی مستند اور اکابر شخصیات کی ایسی تحریروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے جو برداشت، رواداری اور اختلاف رائے میں آداب کی پابندی کی تلقین کرتی ہیں۔
8۔ نزاعی امور پر غیر علمی اور سطحی اظہار خیال کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لیے متعلقہ موضوعات پر سنجیدہ اور بلند پایہ اہل قلم کی تحریروں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے۔
9۔ بہت سے سوالات علمی وفکری یا فقہی سطح پر ابہام کا شکار ہیں اور اس ابہام کی وجہ سے عدم برداشت کے رویوں کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ مثلا تکفیر کے اصول وضوابط اور شرائط کیا ہیں؟ معاشرے میں نہی عن المنکر کی حدود اور آداب اور اس کا دائرۂ اختیار کیا ہے؟ جہاد کا حق اور اختیار کسے حاصل ہے؟ وغیرہ۔ ان مسائل پر پائے جانے والے ابہام کو سنجیدہ علمی بحث ومباحثہ کا موضوع بنائے بغیر فکری ابہام کو دو ر نہیں کیا جا سکتا۔
10۔ برداشت یا عدم برداشت کے مسئلے کو صرف مذہبی طبقات کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے اسے ایک عمومی سماجی رویے کے طور پر لیا جائے اور مختلف مذاہب، برادریوں، طبقات اور فکری وسیاسی دھڑوں کے مابین پائے جانے والے عدم برداشت کے رویوں کو یکساں سطح پر زیر بحث لایا جائے۔
11۔ عدم برداشت اور شدت پسندی کے رویے کے خاتمے کے لیے ان اسباب (سیاسی وسماجی ومعاشی ناہمواری، ظلم ونا انصافی، ناروا اور جارحانہ مذہبی رویے وغیرہ) کو بھی دور کرنا ضروری ہے جن سے یہ رویے پیدا ہوتے ہیں۔
12۔ تاریخ اور سیرت سے ایسی مثالیں تلاش کر کے انہیں منظر عام پر لایا جائے جن میں اختلافات کے باوجود معاشرتی تعلقات قائم رکھے گئے۔ اسی طرح اہل علم حضرات کی جانب سے دیگر اہل علم حضرات کے احترام کے واقعات کو نمایاں کیا جائے۔ حج اور عمرے کے موقع پر ہر طرح کے تنوع اور رنگا رنگی اور تحمل وبرداشت کے جو منظر دیکھنے میں آتے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی جائے۔
13۔ برداشت کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے دوسرے مسلمان یا غیر مسلم ممالک میں جو کامیاب کوششیں کی گئی ہیں، انھیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان سے جو روشنی ملتی ہے، اسے مقامی صورت پر منطبق کرتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔
14۔ مختلف الخیال طبقات (مسلم وغیر مسلم، مذہبی وغیر مذہبی وغیرہ) کے مابین مکالمہ کا عمل ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے اور ایسا کرتے ہوئے شدت پسندانہ رجحانات رکھنے والے عناصر کو نظر انداز کرنے کے بجائے انھیں بھی مکالمہ کے عمل میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے۔
15۔ معاشرے کے مختلف طبقات کے باہمی نزاعات کو صرف ان کا مسئلہ قرار دے کر انہی کے سپرد کر دینے کے بجائے اس رجحان کو فروغ دیا جائے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے مسائل میں دلچسپی لے اور ان کے داخلی نزاعات کو کم سے کم کرنے اور افہام وتفہیم کی فضا پیدا کرنے کے لیے پل کا کردار ادا کیا جائے۔
16۔ معاشرے کی سربرآوردہ شخصیات کی طرف سے سیرت نبوی ؐکی اتباع میں ایسے نمونے پیش کیے جائیں جن میں مخالفین کی طرف سے ناروا یا جارحانہ طرز عمل کا جواب اچھے برتاؤ، حسن سلوک اور درگزر سے دیا جائے۔
17۔ مختلف الخیال طبقات کی اہم شخصیات کے باہمی روابط کا عوامی سطح پر اظہار کیا جائے اور باہمی میل ملاقات اور سماجی تعلقات کو عوام کے سامنے نمایاں کیا جائے تاکہ عوام تک ایک مثبت پیغام پہنچے اور شدت پسندی کے رجحانات میں کمی لائی جا سکے۔
18۔ مختلف طبقات کے ذمہ دار حضرات اپنی تحریروں، بیانات اورخطبات میں مختلف حوالوں سے دوسرے طبقہ ہاے فکر کے خیالات یا خدمات یا ان کے ساتھ اپنے روابط کا ذکر کریں۔ایسے مشترکہ فورمز بھی قائم کیے جائیں جہاں ہر طبقہ فکر سے وابستہ حضرات اجتماعی مسائل پر غور وخوض کریں۔
19۔ ہر طبقہ فکر جس حد تک ممکن ہو، داخلی احتساب کا نظام وضع کرے اور اپنی صفوں کے اندر شدت پسندانہ رجحانات رکھنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے اور کسی بھی حال میں ان کی واضح یا ملفوف تائید نہ کی جائے۔
20۔ پاک انسٹی ٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز اور اس طرح کے دوسرے ادارے مختلف طبقات کے مابین مکالمے کے فروغ کے لیے پل کا کردار ادا کریں اور معاشرتی مسائل پر تجزیاتی ومعلوماتی مواد ہر طبقے کے رجحان ساز افراد تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔
پانچویں گروپ کی سفارشات ’’مدارس کا کردار اور متوازن فکر‘‘ کے عنوان سے تھیں۔ منتظمِ بحث ڈاکٹر ابوالحسن شاہ اور محرکِ بحث مولانا زکریا ذاکر تھے جبکہ مولانا ضیاء نقشبندی، علامہ سید جواد ہادی، مولانا انوارالحق حقانی اور مولانا شمشاد نے شرکا کی حیثیت سے بحث میں حصہ لیا۔ اس گروپ کی مرتب کردہ سفارشات درج ذیل ہیں:
1۔ معاشرے کی خرابی کے ذمہ دار صرف علما اور مدارس ہی نہیں ہیں،اس ضمن میں دیگر عناصر کے کردار پر بھی گفتگو ضروری ہے۔
2۔ طلبہ اور سامعین کو تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔
3۔ ہر طبقہ میں شرپسند اور اختلاف پھیلانے والوں سے براء ت کا اظہار کرنا چاہیے۔
4۔ مدارس کی لائبریری میں تمام مکاتبِ فکر کی کتب ہونی چاہیے۔
5۔ ہر مسلک کی تشریح اس مسلک کا نمائندہ ہی کرے۔
6۔ مدارس میں مثبت اختلافات کی حامل نصابی کتب پر زیادہ توجہ دی جائے۔
7۔ عصری علوم کے بارے میں بنیادی واقفیت اور آگاہی دی جائے۔
8۔ حکومت اہلِ مدارس اور علماء کی معاشی ضروریات کو معاشرے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کرے۔
9۔ علما کی فکری نشو ونما کے لیے اُن کی حالاتِ حاضرہ سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے اہتمام کیا جائے۔
10۔ اساتذہ اور عملہ کی اعلیٰ تربیت کا اہتمام کیاجائے اور ان کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے۔
11۔ فتاویٰ دینے، خاص طور پر دوسرے مسلک کے حوالے سے اختیاط کی جائے۔
12۔ مختلف مکاتبِ فکر میں مشترک نکات کو اجاگر کیاجائے اور فروعی اختلافات کو علمی درسگاہوں تک محدود رکھاجائے اور انہیں اس طرح بیان کیا جائے کہ اختلاف نہ پھیلے۔
13۔ مختلف مذہبی ایام پر مدارس و مساجد میں مشترکہ اجتماعات منعقد کیے جائیں۔
14۔ اہلِ مدارس کی تعلیمی اسناد کو دنیاوی تعلیمی اسناد کے مساوی تسلیم کرکے امتیازی سلوک ختم کیا جائے، تاکہ مدارس سے فارغ التحصیل افراد بھی حکومتی اور نجی اداروں میں اپنی خدمات سرانجام دے سکیں۔
15۔ ’’کسی کے مسلک کو چھیڑو ، نہ اپنے مسلک کو چھوڑو‘‘ کی پالیسی کو عام کیا جائے۔
دماغی رسولی کا آپریشن بذریعہ پسینہ
حکیم محمد عمران مغل
آنے والے ادوار میں جب برصغیر کے اطباء عظام کا شمار کیا جائے گا تو جگراں والے اطبا سرفہرست ہوں گے۔ یہ سارا خاندان حافظ قرآن، حاجی، نمازی، تہجد گزار، غریب پرور، رحم دل اور غم گسار ہے، ایسے کہ اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ حکمت ودانائی ان کے گھر کی لونڈی، جڑی بوٹیاں ان کی غلام۔ یہی وجہ ہے کہ صبح وشام ان کے مطب پر مریضوں کا ازدحام رہتا تھا۔
رسولی اور گلٹی کا تعلق ٹی بی یا سرطان سے بتایا جاتا ہے۔ وکٹوریہ ہسپتال بہاول نگر سے ایک ادھیڑ عمر مریضہ کو ایک صاحب لائے کہ یہ میری چچی ہیں۔ میری ساری پرورش ان کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ان کی موجودہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ پہلے ان کے سر میں ہلکی سی خارش ہوتی رہی جو بعد میں رسولی کی شکل اختیار کر گئی۔ اب ہر جگہ اس کا آخری علاج آپریشن بتایا جا رہا ہے، مگر ان کی خواہش ہے کہ رسولی آپریشن کے بغیر ختم ہو جائے۔ آپ علاج کریں یا کوئی ایسا مشورہ دیں کہ بغیر آپریشن کے رسولی تحلیل ہو جائے۔ میں نے تسلی دی کہ ان شاء اللہ بغیر آپریشن کے رسولی نہ صرف تحلیل ہوگی بلکہ تازیت یہاں دوبارہ پیدا بھی نہیں ہوگی۔
ان دنوں میری مصروفیت حد سے سوا تھا۔ میں نے انھیں مشورہ دیا کہ آپ صدر بازار لاہور میں حکیم جگرانوی صاحب کے پاس چلے جائیں اور میری طرف سے عرض کریں۔ وہ اگلے دن وہاں پہنچے۔ حکیم جگرانوی صاحب کو گزشتہ حالات سے آگاہ کیا۔ انھوں نے چند رسمی باتوں کے بعد فرمایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی اور انشاء اللہ بذریعہ پسینہ رسولی تحلیل ہو جائے گی۔ انھوں نے سات دن کی دوا کے پچیس روپے لیے۔ (یہ تقریباً تیس سال پرانا واقعہ ہے۔) پہلے سات دن میں تو کوئی قابل ذکر افاقہ نہ ہوا مگر اگلے سات دن کے بعد رسولی نے جگہ چھوڑ دی۔ اس طرح دو ماہ سے کم عرصہ سے رسولی کوبذریعہ پسینہ نیست ونابود کر دیا گیا۔
انسانی جسم کی مشین کو چوبیس گھنٹے ٹھنڈا رکھنے سے اور خوراک میں رد وبدل سے رسولیاں اور گلٹیاں نمودار ہوا کرتی ہیں۔ بہاول پور میں گزشتہ کئی سال سے ٹی بی کی لہر آئی ہوئی ہے۔ علامہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق دو ہفتہ متواتر بغیر کسی وقفہ کے آلو کھائے جائیں تو ٹی بی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ آلو چاول بہاول پور والوں کا من بھاتا کھاجا ہے۔ اس پر غور وفکر کی ضرورت ہے۔ انسانی صحت کے لیے پسینہ کی اہمیت پر ایک مستقل مضمون درکار ہے، کبھی عرض کروں گا۔ آج کل جتنے جلدی امراض ہیں، ان میں سے پچاس فی صد امراض پسینے میں شرابور رہنے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اطبا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ پسینہ صحت کا خزینہ ہے۔ اطبا کے ہاں صدیوں پرانا جوشاندہ ان امراض میں بڑے نام کا اور بڑے کام کا مانا گیا ہے۔ اس سے پسینہ فوری آتا ہے اور گلٹیوں اور رسولیوں کو تحلیل کر جاتا ہے۔ ٹھنڈے مشروبات پینے کے بعد اے سی اور پنکھوں کی ہوا سے لطف اندوز ہونے والے حضرات گردو ں اور جگر کی بیماریوں اور جوڑوں کے درد سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بند ڈبوں کی تمام اشیا، حلوائی اور بیکری کی تمام مصنوعات کا ان امراض کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان پائیں چھٹکارا یا پھر ان بیماریوں کو کریں گوارا!
ستمبر ۲۰۱۱ء
دینی جدوجہد اور اس کی اخلاقیات
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
آج میں اپنی ’’قادیانیت نوازی‘‘ کی داستان قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے الزام کا مجھے گزشتہ چار پانچ برسوں سے بعض دوستوں کی طرف سے سامنا ہے اور اب اس الزام کا ہدف ہونے میں عزیزم حافظ محمد عمار خان ناصر بھی میرے ساتھ شریک ہو گیا ہے۔
چند برس پہلے کی بات ہے، پسرور کے ایک سن رسیدہ بزرگ قاضی عطاء اللہ صاحب میرے پاس تشریف لائے۔ وہ ایک سابق قادیانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر نصف صدی قبل مسلمان ہو گئے تھے اور اب بحیثیت مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ انھوں نے قرآن کریم کے مختلف تراجم کو سامنے رکھ کر ترجمہ قرآن کریم کو منظوم شکل میں پیش کیا ہے اور ’’مفہوم القرآن‘‘ کے نام سے اسے شائع کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ان کے پاس تھا اور وہ اس پرمجھ سے تقریظ لکھوانا چاہتے تھے۔ میں ان سے براہ راست واقف نہیں تھا اور ان کے ساتھ سابق قادیانی ہونے کا لاحقہ بھی ان کی گفتگو سے میرے علم میں آ چکا تھا، اس لیے میں نے ان سے کتاب لے کر رکھ لی اور عرض کیا کہ چند روز کتاب دیکھنے کے بعد کچھ لکھ سکوں گا۔ اس قسم کے معاملات میں میرا معمول یہ ہے کہ مقامی علماء کرام سے رجوع کرتا ہوں اور ان کی جو رائے ہو، ا س پر عمل کرتا ہوں۔ بادشاہی مسجد پسرور کے خطیب حضرت مولانا مفتی رشید احمد پسروری ان دنوں حیات تھے اور میرے بزرگ دوستوں میں سے تھے۔ ان سے ایک جگہ ملاقات ہوئی اور میں نے قاضی عطاء اللہ صاحب کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ قادیانی تھے، مگر اب صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ اس پر میں نے اس کتاب کو چند جگہ سے دیکھا اور کچھ سطروں میں تقریظ لکھ دی جو انھوں نے کتاب کے اگلے ایڈیشن میں شامل کر دی۔
اس پر بعض دوستوں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ میں نے ایک قادیانی کی تفسیر قرآن کریم پر تقریظ لکھ دی ہے۔ صرف اعتراض نہیں ہوا بلکہ ملک بھر میں اس کی خوب تشہیر کی گئی، چنانچہ مختلف شہروں سے مجھے فون آنے لگے، بلکہ عام حلقوں میں تقسیم کیے جانے والے ایک پمفلٹ میں اس اعتراض کا ذکر کیا گیا جس پر میں نے قاضی عطاء اللہ موصوف سے رابطہ کیا تو وہ ایک بڑی فائل لے کر میرے پاس آ گئے جو ان کے قادیانی ہونے کے اخباری پراپیگنڈا اور ان کی طرف سے جوابات پر مشتمل تھی اور ان کا ایک حلف نامہ بھی اس میں شامل تھا جس میں پوری وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور قادیانی نہیں ہیں۔ اس حلف نامہ میں انھوں نے اپنے عقائد کا بھی دوٹوک انداز میں ذکر کیا ہے اور اس پر پسرور کے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے معروف علماء کرام کی تصدیقات ہیں۔ اس کے بعد ایک موقع پر میں پسرور گیا تو مختلف علماء کرام سے براہ راست بھی اس مسئلے پر بات کی۔ انھوں نے پورے اطمینان کے ساتھ بتایا کہ قاضی صاحب موصوف پر قادیانی ہونے کا الزام غلط ہے اور وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود نہ صرف پراپیگنڈا مہم جاری رہی بلکہ مسلسل لابنگ بھی ہوتی رہی، چنانچہ ہمارے اپنے مدرسہ جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے دو بزرگ اساتذہ حضرت مولانا سید عبد المالک شاہ صاحب اور حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کی تحریری وضاحت طلب کی اور تقاضا کیا کہ میں قاضی عطاء اللہ موصوف کی کتاب ’’مفہوم القرآن‘‘ پر اپنی تقریظ سے رجوع کا اعلان کروں۔ اس پر میں نے ایک بار پھر پسرور کے علماء کرام سے رابطہ کیا مگر صورت حال میں کوئی تبدیلی نہ پا کر تقریظ واپس لینے سے معذرت کر دی اور دونوں بزرگوں کو تحریری طو رپر اصل صورت حال اور اپنے موقف سے آگاہ کر دیا۔
میرا خیال تھا کہ ا س کے بعد یہ مہم ختم ہو جائے گی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، البتہ اس کا رخ بدل گیا اور معترض دوستوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے قائم کردہ ’’متحدہ علماء بورڈ‘‘ کو درخواست دی کہ یہ کتاب ایک قادیانی نے لکھی ہے اور اس میں قادیانی عقائد کا پرچار کیا گیا ہے، اس لیے اس پر پابندی لگائی جائے۔ متحدہ علماء بورڈ کے سربراہ حضرت مولانا پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب آف بھیرہ شریف ہیں۔ وہ میر ے مہربان اور بزرگ دوستوں میں سے ہیں۔ انھوں نے کتاب پر میری تقریظ دیکھی تو چونک گئے کہ ایک قادیانی کی کتاب پر میری تقریظ کیسے ہو سکتی ہے؟ انھوں نے مہربانی فرما کر مجھ سے فون پر براہ راست رابطہ کر لیا۔ میں نے انھیں صورت حال سے آگاہ کیا اور گزارش کی کہ آپ جو مناسب سمجھیں، فیصلہ کریں، لیکن میری درخواست صرف اتنی ہے کہ اس سلسلے میں میرے پاس متعلقہ کاغذات کی ایک فائل ہے، اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو فیصلہ چاہیں، کر لیں۔ حضرت پیر صاحب محترم کے ارشاد پر میں نے وہ فائل انھیں بھجوا دی۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ انھوں نے کیا فیصلہ فرمایا۔
مگر بات یہاں بھی نہیں رکی اور پاکستان شریعت کونسل میں میرے قریب کے ساتھیوں سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ مجھے اپنے موقف پر نظر ثانی کے لیے کہیں۔ مولانا عبد الحق خان بشیر میرے حقیقی بھائی ہیں اور پنجاب شریعت کونسل کے امیر ہیں جبکہ لاہور باغبان پورہ کے مولانا قاری جمیل الرحمن اختر میرے حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں اور مرکزی شریعت کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ دونوں حضرت میرے پا س الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں تشریف لائے اور اس مسئلے پر مجھ سے تفصیلی بات کی۔ میں نے گزارش کی کہ مجھے اپنے موقف پر اس قدر اصرار نہیں ہے کہ اس پر کسی کی بات نہ سنوں۔ آپ دونوں حضرات خود پسرور تشریف لے جائیں اور اپنے طور پر وہاں کے علماء کرام سے بات کر کے تحقیق کریں۔ اس کے بعد آپ دونوں حضرات جو بھی کہیں گے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، چنانچہ یہ دونوں حضرات پسرور تشریف لے گئے اور اپنے طور پر صورت حال معلوم کی۔ واپسی پر انھوں نے جو رپورٹ پیش کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قاضی عطاء اللہ صاحب کو قادیانی قرار دینے کی بات تو درست نہیں ہے، البتہ ان کی اس کتاب کے بعض مندرجات پر اشکالات ہیں اور ان سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان عبارات سے قادیانیوں کی بعض باتوں کی حمایت کا تاثر ملتا ہے۔ ان کی اگر وضاحت ہو جائے تو مناسب ہوگا۔ اس حوالے سے قاضی صاحب سے میری بات ا س سے قبل بھی ہو چکی تھی اور انھوں نے صاف طو رپر کہہ دیا تھا کہ وہ عالم دین نہیں ہیں اور نہ ہی انھوں نے قرآن کریم کا ازسرنو کوئی ترجمہ کیا ہے، بلکہ انھوں نے اردو تراجم کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کے اردو ترجمہ کو منظوم شکل دی ہے، اس لیے علماء کرام جہاں بھی کوئی اشکال محسوس کریں، اس کی نشان دہی کر دیں۔ میں ا س عبارت کی اصلاح کر دوں گا، مگر مولانا عبد الحق خان بشیر اور مولانا قاری جمیل الرحمن اختر کی پسرور سے واپسی کے بعد میں نے دوبارہ قاضی عطاء اللہ صاحب سے رابطہ کیا اور وہ میرے پاس تشریف لائے۔ ان کا موقف اب بھی وہی تھا کہ علماء کرام کتاب کا مطالعہ کر کے نشان دہی کریں۔ جو عبارت بھی مشتبہ ہوگی، وہ اسے تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ اب وہ کتاب میں نے نظر ثانی اور تفصیلی مطالعہ کے لیے مولانا عبدالحق خان بشیر کو دے دی ہے اور ان کی ابتدائی رپورٹ یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی واضح عبارت تو نظر نہیں آئی، البتہ بعض عبارات سے اشتباہ ہوتا ہے جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
یہ تو میرے ’’قادیانی نواز‘‘ ہونے کی داستان ہے اور اب عزیزم عمار خان بھی اس الزام میں میرے ساتھ شریک ہو گیا ہے۔ عمار خان نے اسلامی نظریاتی کونسل کے رسالہ ’’اجتہاد‘‘ میں اجتہادی رویوں اور دینی تحریکات کی حکمت عملی کے حوالے سے ایک مضمون لکھا جو ’’اجتہاد‘‘ کے بعد ماہنامہ الشریعہ کے دسمبر ۲۰۱۰ء کے شمارہ میں بھی شامل ہوا۔ اس میں اس نے قادیانیوں کے بارے میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے حوالے سے لکھا کہ:
’’اگر کسی معاشرے میں کشف والہام انفرادی دائرے سے اٹھ کر ایک باقاعدہ اداراتی صورت اختیار کر چکے ہوں، ان کی بنیاد پر شخصیات اور جماعتوں کے عند اللہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کیے جاتے ہوں، لوگوں کو ان کی طرف دعوت جاتی اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کو نجات کی بشارت دی جاتی ہو، القا والہام کی بنیاد پر مراقبہ وسلوک کے نظام مرتب کیے جاتے بلکہ سیاسی ومذہبی اختلافات میں بھی حق وباطل کی تفریق کرنا ایک عام چلن ہو، جہاں خواب اور بشارات کسی کے مامور من اللہ ہونے کا ایک مستند ذریعہ سمجھے جاتے ہوں، ایسی فضا میں اگر کوئی شخص ’’شبانی سے کلیمی دو قدم ہے‘‘ کا نعرۂ مستانہ بلند کر دے اور عام لوگ اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اسے ایک ’’امتی نبی‘‘ مان لیں تو انھیں کس حد تک اس کا قصور وار ٹھہرایا جا سکتا اور راہ راست پر لانے کی ہمدردانہ کوشش کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے محض ان کا معاشرتی مقاطعہ کرنے اور قانونی اقدامات کے ذریعے سے انھیں مسلمانوں سے الگ کر دینے پر اکتفا کے طرز عمل کو کس حد تک اخلاق، حکمت اور دعوت دین کے تقاضوں کے مطابق قرار دیا جا سکتا ہے؟ ‘‘ (الشریعہ، دسمبر ۲۰۱۰، ص ۴۸)
عزیزم عمار کی اس عبارت پرملک کے مختلف دینی جرائد میں تبصرہ شائع ہوا ہے اور اس عبارت سے یہ مطلب اخذکیا گیا ہے کہ ’’امتی نبی‘‘ ہونا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اور قادیانیوں کے معاشرتی مقاطعہ اور ان کے خلاف قانونی اقدامات کا طرز عمل درست نہیں ہے، حالانکہ تھوڑے سے غور وخوض کے بعد یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس عبارت میں:
- تصوف میں مبالغہ آرائی کی بعض صورتوں پر طنز کیا گیا ہے جو خود میرے نزدیک بھی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ بات اس سے بہتر اسلوب میں بھی کہی جا سکتی تھی۔
- اس طرز عمل کو عام مسلمانوں کے قادیانی فریب سے متاثر ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے اور
- فریب کاری سے متاثر ہونے والے سادہ لوح مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انھیں ہمدردی کے ساتھ اس فریب سے نکالنے اور اسلام میں واپس لانے کی تدابیر اختیار کی جانی چاہییں۔
یہ مضمون الشریعہ کے دسمبر ۲۰۱۰ء کے شمارے میں شائع ہوا ہے، جبکہ اس سے قبل مارچ ۲۰۱۰ء کے شمارے میں مولانا مشتاق احمد چنیوٹی کی تصنیف ’’اقبالؒ اور قادیانیت‘‘ پر تبصرہ کرتے ہوئے عمار خان اپنا یہی موقف ان الفاظ میں لکھ چکا ہے کہ:
’’انیسویں صدی کے آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ظلی نبوت کے عنوان سے برصغیر میں ایک نیا باب الفتن کھولا تو سادہ لوح عوام کو اس کے دجل وفریب سے آگاہ کرنے کے لیے اہل حق کو میدان میں آنا پڑا اور اہل علم نے علمی وتحقیقی اور مناظرانہ ومجادلانہ، ہر دو انداز میں پوری مستعدی سے قادیانی نبوت کی تاویلات وتحریفات کا پردہ چاک کیا۔ اہل دین کی کم وبیش پون صدی کی مسلسل جدوجہد قادیانی فرقے کو عالم اسلام میں قانونی اور آئینی سطح پر غیر مسلم قرار دینے پر منتج ہوئی۔ اس تحریک کی قیادت اور راہ نمائی بنیادی طور پر علما نے کی، تاہم اس کی کامیابی میں بہت سی ایسی شخصیات کا حصہ بھی کم نہیں جو روایتی مذہبی حلقے کی نمائندہ نہیں سمجھی جاتیں۔ ان شخصیات میں علامہ محمد اقبالؒ کا نام سرفہرست ہے۔
قادیانی گروہ نے اپنی معاشرتی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو مذہبی تاویلات اور گورکھ دھندوں میں الجھانے کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی اور سماجی عوامل کا بھی سہارا لینے کی کوشش کی۔ برصغیر کی فضا مختلف مذہبی گروہوں کی طرف سے ایک دوسرے کی تکفیر کے واقعات سے مانوس تھی، جبکہ مرزا غلام احمد دعواے نبوت سے پہلے کئی سال تک ہندووں اور عیسائیوں کے مقابلے میں دفاع اسلام کے محاذ پر محنت کر کے اپنے حق میں ہمدردی کی فضا بڑے پیمانے پر پیدا کر چکے تھے، چنانچہ جب ان کے دعواے نبوت پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تو ایک وقت تک ناواقف مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسے روایتی مذہبی فتوے بازی ہی کا ایک نمونہ سمجھتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انگریز سرکار بلکہ اسلام سے محض نسبت کا تعلق رکھنے والے نام نہاد لبرل طبقات کی ہمدردیاں بھی اس نوزائیدہ گروہ کو حاصل تھیں۔ اس تناظر میں علامہ اقبال جیسی قد آور اور معتبر ملی شخصیت کا قادیانی نبوت کے خلاف دو ٹوک اور واضح موقف اختیار کرنا ان تمام طبقات پر مذہبی علما کے موقف کا وزن واضح کرنے میں بے حد موثر ثابت ہوا جو کسی بھی وجہ سے اس معاملے میں تردد یا دو ذہنی کا شکار تھے۔
زیر نظر کتابچہ میں مولانا مشتاق احمد چنیوٹی نے، جو اس موضوع کے متخصص ہیں، قادیانیت کے بارے میں علامہ محمد اقبال کی تحریروں، گفتگووں اور بیانات کا ایک مختصر مگر نمائندہ انتخاب جمع کر دیا ہے جو اس حوالے سے ان کے زاویہ نظر اور استدلال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کے طرز استدلال کا ایک امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے عقیدۂ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدمہ خالص کلامی بنیاد پر پیش کرنے کے بجائے پنے مخاطب طبقات کی ذہنی رعایت سے، اس عقیدے کی اہمیت کو سماجی اصولوں کی روشنی میں واضح کیا اور یہ بتایا کہ بحیثیت ایک گروہ کے مسلمانوں کے مذہبی تشخص کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے اور اس کی حفاظت کے لیے یہ ان کا مذہبی، اخلاقی اور جمہوری حق ہے کہ کسی نئی نبوت پر ایمان لانے والے گروہ کو ان کا حصہ سمجھنے کے بجائے ایک نیا مذہبی گروہ قرار دے کر قانونی اعتبار سے ان سے الگ کر دیا جائے۔ (ص ۱۶، ۱۷)
اسی طرح انھوں نے قادیانی گروہ پر زندقہ وارتداد کے روایتی فقہی احکام (یعنی سزاے موت) جاری کرنے کے بجائے جدید جمہوری تناظر میں یہ تجویز کیا کہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کر لیا جائے اور پھر مسلمان ان کے بارے میں ویسے ہی مذہبی اور معاشرتی رواداری سے کام لیں گے جیسے وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لیتے ہیں۔ (ص ۱۱) یہ بات اس پہلو سے بہت اہم اور حکیمانہ تھی کہ قانونی تکفیر کے باوجود اس سے آگے چل کر ان ہزاروں لوگوں کے لیے اسلام کی طرف واپسی کا راستہ کھلا رہتا جو مختلف وجوہ سے قادیانیت کے پرفریب جال کا شکار ہو کر جادۂ حق سے بھٹک گئے، جبکہ موجودہ صورت حال میں مسلمان مناظرین کے اختیار کردہ لب ولہجہ اور طرز استدلال نیز قادیانیوں کی نئی نسل کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط بالکل مفقود ہونے کی وجہ سے یہ راستہ کم وبیش بند دکھائی دیتا ہے، چنانچہ مرزا طاہر احمد کے دست راست حسن محمود عودہ نے بیس سال قبل اپنے قبول اسلام کے موقع پر ایک انٹرویو میں قادیانی امت کے اپنی گمراہی پر قائم رہنے کا ایک بڑا سبب اس چیز کو قرار دیا تھا کہ ان کی مسلمان علما تک رسائی نہیں ہے اور قادیانی قیادت اس خلیج کو برقرار رکھنے میں ہی اپنا بھلا سمجھتی ہے۔ ‘‘
’الشریعہ‘ کے مارچ ۲۰۱۰ء کے شمارے میں شائع ہونے والے اس تفصیلی موقف پر نظر ڈالنے کے بعد دسمبر ۲۰۱۰ء کے شمارے میں شائع ہونے والے مضمون کے اس اجمالی اقتباس کو پھر سے ملاحظہ فرما لیا جائے کہ اس میں قادیانیوں کی حمایت کی گئی ہے یا ان کے فریب کا شکار ہونے والے سادہ لوح مسلمانوں کو فریب کے اس دائرے سے ہمدردی کے ساتھ نکال لانے کی بات کہی گئی ہے؟ ہم تو ان دوستوں سے صرف یہی عرض کر سکتے ہیں کہ
سخن فہمی عالم بالا معلوم شد
۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت کی بات ہے۔ میں اس وقت کل جماعتی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع گوجرانوالہ کا سیکرٹری تھا اور مرکزی جامع مسجد چونکہ تحریک کامرکز تھی، اس لیے تحریک کے تنظیمی اور دفتری معاملات کا انچارج بھی تھا۔ ضلع گوجرانوالہ کے ایک قصبے میں تحریک کے جلسے کاپروگرام تھا جس میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت کے لیے اے سی کو درخواست دے رکھی تھی۔ راقم الحروف تحریک ختم نبوت کے ایک اور راہ نما کے ساتھ اے سی گوجرانوالہ سے ملا کہ وہ اجازت دے دیں۔ انھوں نے حالات کی خرابی اور جھگڑے کے خدشے کے عنوان سے ٹال مٹول کرنا چاہی۔ میرے ساتھ جانے والے دوست نے اچانک ان سے کہہ دیا کہ آپ قادیانی تو نہیں ہیں؟ اے سی کچھ گھبرا سا گیا اور یہ کہہ کر منظوری کے دستخط کر دیے کہ مولوی صاحب! اتنا بڑا الزام مجھ پر نہ لگائیں اور جائیں، جا کر جلسہ کریں۔
اے سی کے دفتر سے باہر نکلے تو مولوی صاحب سے میں نے کہاکہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے کہا کہ اس کے بغیر وہ اجازت نہ دیتا۔ اس وقت تو میں نے بھی محسوس نہ کیا کہ ہم جس کام کے لیے گئے تھے، وہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ بات آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئی کہ ہم بسا اوقات اپنا کام نکلوانے کے لیے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے بھی کسی اچھے بھلے مسلمان کو قادیانی کہہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کے بعد تحریکی زندگی میں بہت سے مراحل ایسے آئے کہ اچھے خاصے بزرگوں کی طرف سے بھی اسی قسم کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا پڑا۔
پنجاب کے سابق آئی جی پولیس احمد نسیم چودھری گکھڑ کے رہنے والے ہیں۔ میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں۔ انھوں نے قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم ہمارے گھر میں ہماری والدہ محترمہ سے حاصل کی ہے اور ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز کے خاص عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ ضلع جھنگ کے ایس ایس پی تھے۔ ایک روز حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ گوجرانوالہ میرے پاس تشریف لائے اور باتوں باتوں میں فرمایا کہ ہمارے ضلع کا ایس ایس پی مرزائی ہے۔ میں نے چونک کر دریافت کیا کہ کیا ضلع جھنگ کا ایس ایس پی تبدیل ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، وہی احمد نسیم ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ حضرت! آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں نے تحقیق کر لی ہے، وہ قادیانی ہے اور اس کا نام بھی قادیانیوں والا ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! آپ اسے نہیں، مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں۔ مولانا چنیوٹی بھی چونکے اور فرمایا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ میرا دوست ہے، بھائی ہے، کلاس فیلو ہے اور حضرت والد صاحب کے شاگردوں میں سے ہے۔ پھر میں نے مولانا چنیوٹی کو احمد نسیم چودھری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تو بڑے پریشان ہوئے۔ قارئین کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں احمد نسیم چودھری لاہور کے ایس ایس پی تھے، اخبارات میں ان کے خلاف بعض حلقوں کا بیان شائع ہوا تھاکہ لاہور کے ایس ایس پی نے لاہور کے تھانوں کی مساجد میں دیوبندی اماموں کی بھرمار کر دی ہے۔
مولانا چنیوٹی میری بات سن کر الجھن میں پڑ گئے اور فرمایا کہ مجھے اس کے ایک ڈی ایس پی نے بڑے وثوق کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ا س بات کی تحقیق کریں کہ اس ڈی ایس پی نے ایسا کیوں کہا ہے؟ کچھ دنوں بعد مولانا چنیوٹی نے خود مجھے بتایا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے۔ اس ڈی ایس پی کا کوئی کام ایس ایس پی نے نہیں کیا تھا اور ا س نے غصہ نکالنے کے لیے اس عنوان سے مجھے استعمال کرنا چاہا،مگر تم نے اچھا کیا کہ مجھے بروقت آگاہ کر دیااور میں اس سے بچ گیا۔ اس کے بعد میری درخواست پر احمد نسیم چودھری اور مولانا چنیوٹی کی باہم ملاقات ہوئی اور پھر ان کے درمیان بہت اچھے دوستانہ مراسم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
مولانا چنیوٹی چونکہ اس محاذ کے جرنیل تھے اور ان کی بات کو اس حوالے سے سند سمجھا جاتا تھا، اس لیے بعض لوگ مولانا موصوف کی اس پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ناروا کوشش کرتے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا چنیوٹی کہیں جاتے ہوئے میرے پاس گوجرانوالہ میں رکے اور بریف کیس سے ایک فائل نکال کر مجھے دکھائی کہ گکھڑ کا ایک شخص غالباً بحرین کے پاکستانی سفارت خانے میں افسر ہے جس کے بارے میں وہاں سے بعض پاکستانیوں کے خطوط آئے ہیں جن کی ساہیوال کے ایک بڑی دینی جامعہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ شخص قادیانی ہے اوربحرین کے پاکستانیوں کو تنگ کر رہا ہے۔ چونکہ وہ گکھڑ کا رہنے والا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ میں نے نام پوچھا تو بتایا کہ اس کا نام شعبان اپل ہے۔ میرے دونوں ہاتھ بے ساختہ کانوں تک چلے گئے کہ اس کا معاملہ بھی احمد نسیم چودھری کی طرح کا تھا۔ وہ ہمارا پڑوسی تھا۔ ہمارا بچپن اکٹھے گزرا۔ میں نے لکھنا پڑھنا اس کی ہمشیرہ سے سیکھا اور اس نے قرآن کریم میری والدہ مرحومہ سے پڑھا۔ اس کی والدہ اور میری والدہ آپس میں سہیلیاں بنی ہوئی تھیں اور ہم اس کی والدہ کو خالہ جی کہا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی یاد آتی ہے تو اس دور کی حسین یادیں دل میں گدگدی کرنے لگتی ہیں۔ میں نے وہ فائل ایک نظر دیکھی اوریہ کہہ کر مولانا چنیوٹی کو واپس کر دی کہ اس نے کسی کا کام نہیں کیا ہوگا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کر دی ہے۔ مولانا چنیوٹی بھی فرمانے لگے کہ اچھا ہوا، میں نے تم سے پوچھ لیا، ورنہ میں بحرین کی حکومت اور پاکستان کی حکومت دونوں کو باضابطہ خط لکھنے والا تھاکہ اس افسر کو بحرین کے پاکستانی سفارت خانے سے واپس کیا جائے۔
بعض واقعات تو اس سے بھی زیادہ خوف ناک ہیں جو میرے حافظے میں محفوظ ہیں، مگر ایک اور واقعہ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ گوجرانوالہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں سرکردہ علماء کرام کا ڈویژنل سطح پر اجلاس تھا۔ اس میں ضلع سیالکوٹ کے ایک محترم بزرگ نے بڑے وثوق کے ساتھ اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب کا سیکرٹری تعلیم قادیانی ہے، اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ اجلاس کے بعد میں نے ان سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے اور آپ نے تحقیق کر لی ہے؟ انھوں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ ہاں، وہ بہت پکا قادیانی ہے۔ ضیاء الحق مرحوم کا دور حکومت تھا اور ان کے ایک مشیر کے ساتھ جو تعلیم کے شعبہ ہی کے مشیر تھے، میری علیک سلیک تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میرا اسلام آباد جانے کا پروگرام بن گیا اور میں نے طے کیا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے اس مشیر سے اس سلسلے میں خود بات کروں گا۔ ان دنوں میرے ایک پرانے دوست پروفیسر افتخار احمد بھٹہ وفاقی وزارت تعلیم میں افسر تھے۔ پہلے میں نے ان سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور خیال کیا کہ انھیں بھی ملاقات میں ساتھ لے جاؤں گا۔ انھوں نے میری بات سنی تو فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے بات کر لی، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جاتی، اس لیے کہ جن صاحب کے پاس تم یہ شکایت لے کر جا رہے ہو، یہ ان صاحب کے داماد ہیں جن کی شکایت کرنے آئے ہو اور دونوں میں سے کوئی بھی قادیانی نہیں ہے۔ میرے کچھ اور کام بھی تھے، مگر پروفیسر افتخار احمد بھٹہ کی یہ بات سن کر میں اتنا کنفیوژ ہوا کہ میں نے سرے سے ان مشیر صاحب سے ملاقات کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور واپس گوجرانوالہ چلا آیا۔
عقیدۂ ختم نبوت کے لیے جدوجہد کرنا عبادت ہے اور قادیانیوں کا ہر محاذ پر تعاقب کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، لیکن ہر جدوجہد اور محاذ کی کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ پھر ہمارا دین تو ’’دین اخلاق‘‘ کہلاتا ہے اور ہم ساری دنیا کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اخلاق عالیہ کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ کیا خود ہمارے لیے ان اخلاقیات کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین
قومی ہم دردی اور ہم
مولانا محمد بدر عالم
لکڑی کا بنا ہواخوبصورت دروازہ گھرسے نکلتے وقت آپ کو الوداع کرتاہے اورگھر میں داخل ہوتے وقت آپ کا استقبال کرکے آپ کادل خوش کرتااوراپنی مضبوطی کا احساس دلاتا ہے ۔ایک دن اچانک جیسے ہی آپ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہیں کسی ایک پٹ کا کوئی قبضہ اکھڑ جاتاہے ۔چوکھٹ کے کسی ایک بازوسے لکڑی کا چھلکا ادھڑ کر ہاتھ میں آجاتاہے۔ یہ کیا؟آپ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں اورفوراہی آپ کو معلوم ہوجاتاہے کہ یہ دابۃ الارض(دیمک ) کی کارستانی ہے۔ ایسی چوکھٹ کا کیا فائدہ اسے تو تبدیل کرنا پڑے گا۔ پکانے کے لیے بڑے شوق سے آپ چنے یا سفید لوبیا لے کر آئے۔ دھونے کے لیے برتن میں ڈالا، مگر یہ کیا؟ اس کے آدھے سے زیادہ دانے تو اندر سے کھوکھلے ہیں۔یہ پکانے کے قابل نہیں رہے۔ چوکھٹ اوردانے دشمن کا شکار ہوگئے جواگرچہ باہر سے آیا، مگر اندر ہی اندرکام کرتے ہوئے اس نے انہیں داخلی طورپر کھوکھلاکردیا۔ امتوں اورقوموں کے عروج وزوال کی داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میرامحدودمطالعہ اورتجزیہ مجھے یہی بتاتاہے کہ اقوام کاعروج اورزوال دونوں اندر سے شروع ہوتے ہیں۔ داخلی عوامل ہی ان دونوں کا اصل سبب ہوتے ہیں۔جن خارجی اثرات کو ان کا سبب سمجھاجاتاہے، وہ دراصل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ایک نعرہ لگایاجاتاہے :
گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو
خارجی اثرات صرف ایک دھکے کاکام کرتے ہیں۔ہم اپنی تباہی کے اسباب خارج میں ڈھونڈتے ہیں اورانہیں دور کرنے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں۔بنیاد مضبوط کیے بغیر ہی بلند وبالاعمارت کی تعمیر شروع کردیتے ہیں جو تکمیل سے پہلے ہی گرجاتی ہے۔جیسے معدے کا مزاج فاسد ہوجائے تو عمدہ سے عمدہ غذا بھی زہر بن جاتی ہے، اسی طرح اندرونی بیماریاں دور کیے بغیرخارجی کمزورری دور کرنے کی ہرکوشش بیماری کو بڑھاتی اورمسائل میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ہمیں یہ یاد رکھناچاہیے کہ ہمارا دشمن ہم پر کسی ایک جہت سے حملہ آور نہیں ہے، بلکہ اس کا حملہ ہمہ جہت ہے ۔فکری حملہ، عسکری حملہ، سیاسی حملہ، معاشی حملہ ،معاشرتی حملہ، تعلیمی حملہ۔ پھر ان حملوں کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتاہے، اس لیے دفاع بھی ہمہ جہتی ہوگا۔ جو لوگ کسی ایک راستے کو اختیار کرتے اورپھر اسی کو حرف آخر قرار دے کر تما م لوگوں پر اس کی پابندی لازم کردیتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں ۔صحیح معنوں میں یوں کہاجائے کہ وہ لوگوں کی نفسیات اوراختلاف طبائع کے برخلاف معاملہ کرتے ہیں جن پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ چند معاملات مستثنیٰ ہیں جن میں رعایتیں موجودہیں، مگراختلاف طبائع کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ہاں اتنا لازم ہے کہ دفاع اوراقدام سے پہلے ایک عمومی مضبوط بنیاد بنالی جائے جو ہر شعبے میں کام دے سکے ۔
معاشرہ افراد سے بنتاہے اورقوم معاشرے سے ہی تشکیل پاتی ہے ۔فرد کی تعمیر وتخریب ہی معاشرے کی تعمیر وتخریب کی بنیاد ہوتی ہے ۔فرد کی تعمیر اخلاق وکردار سے ہوتی ہے۔علم الاخلاق ایک باقاعدہ موضوع ہے جس کے اندر بہت سے اخلاق پر بحث کی جاتی ہے، مگر یہاں میرامقصود وہ تمام اخلاق اوران کا فلسفہ بیان کرنانہیں اگرچہ ان سے بالکل اجتناب بھی ممکن نہیں۔ میری مراد وہ چند اہم اخلاق ہیں جو معاشرے کو قوم اوربھیڑ کو فوج بناتے ہیں، جو اختلاف طبیعت، اختلاف نسل، اختلاف زبان وغیرہ کے باوجودپورے سماج کو ایک لڑی میں پرودیتے ہیں،جس کی ہر اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے،جس میں فرد حصار ذات سے بلند ہوکر کام کرتاہے۔جب اخلاق کو گھن لگ جاتاہے تو قوموں کی سطوت وشوکت کے بلند وبالامحل بھی پیوند خاک ہوجاتے ہیں اوران کی رفعت وعروج کے مضبوط دروازے بھی دیمک کا شکار ہوجاتے ہیں۔مضبوط اخلاقی کردار ہی میرے نزدیک وہ عمومی بنیاد ہے جو تمام شعبوں میں کام کرنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔حضرت تھانوی کا ایک مقولہ کہیں پڑھاتھا کہ مجھے اگر امیر المومنین بنادیاجائے تودس سال تک کے لیے جہاد کا اعلان نہ کروں، بلکہ اس عرصے میں قوم کی اخلاقی تربیت کا کام کیا جائے۔الفاظ آگے پیچھے ہوگئے، مفہوم ایسا ہی تھا۔
جب معاشرے کے عام افرادمیں اخلاقی گراوٹ کے آثاررونما ہوں تو اس کا مطلب ہوتاہے کہ قوم کے اندر بیماری پیدا ہوچکی ہے جو علاج کا تقاضاتو کرتی ہے مگر ایسی بیماری ہے جو اطراف میں ہے ،اورجب قوم کا مقتدر طبقہ اس علت کا شکار ہوجائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اعضائے رئیسہ دل، دماغ، جگر پر بیماری کا حملہ ہوجائے۔جو افراد قوم کا مکھن اوربالائی سمجھتے جاتے ہوں، جب وہ خراب ہوں تویہ اس بات کی دلیل ہے کہ لسی اوردودھ میں اس پہلے شدید خرابی پیداہوچکی ہے۔ مسلم قوم بھی اخلاقی گراوٹ کے انہی داخلی عوامل کی وجہ سے روبہ زوال ہوئی۔ دیکھیے احادیث میں بھی اخلاقی بیماریوں ہی کو مسلم امہ کی مغلوبیت کا سبب بتایا۔ ایک معروف طویل حدیث میں ہے کہ ’’وہن‘‘ کی وجہ سے کافر اقوام مسلمانوں پر حملے کے لیے باہم اس طرح دعوت دیں گی جس طرح لوگوں کو دسترخوان کی طرف بلایا جاتاہے، حالاں کہ اس وقت مسلمان سمند ر کے جھاگ کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے ’’وہن‘‘ کی بابت دریافت کیا تو فرمایا: حب الدنیا و کراھیۃ الموت، دنیاکی محبت اورموت سے نفرت ۔ایک دوسری حدیث میں فرمایا: حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیاکی محبت ہربرائی کی جڑہے ۔حب دنیاکو موت سے کراہت لازم ہے اورحب دنیاسے جو بنیادی خرابیاں پیداہوتی ہیں، وہ اخلاقی بیماریاں ہی ہیں ۔
جیساکہ پہلے ذکر کرچکاہوں کہ قوم کی ترقی کے لیے چند مخصوص اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ان اخلاق کو اپنے اندر پیداکرنے کے لیے اس درجے کی محنت کی ضرورت نہیں جو تصفیہ قلوب کے نام سے خانقاہوں میں ہوتی ہے، اگر چہ فی نفسہ اس محنت کی ضرورت واہمیت سے انکار نہیں بلکہ دیگر ذرائع کے ساتھ خانقاہی نظام کوان اہم اخلاقی صفات کے پیداکرنے اوران کے مطابق فردکی تربیت کرنے میں اہم کرداراداکرسکتاہے۔
جن اخلاق کی ہم بات کررہے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم خلق عصبیت ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیاہے، اس کے مختلف مظاہر دکھائے ہیں اوراسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں عصبیت کی کارفرمائی کا جائزہ لیاہے۔ عصبیت اگر حد کے اندر رہے اورحق سے ناحق کی طرف جانے نہ پائے تو یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے کوئی فرداپنی قوم کی آن،عزت ،آبرواوربقاکے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوجاتاہے۔ وہ اپنی قوم کی خاطر ہرطرح کے ایثار اورقربانی سے کام لیتاہے۔عصبیت کے اندر ہی وہ صفت چھپی ہوتی ہے جو میرے اس مضمون کا موضوع ہے۔بدقسمتی یہ ہے کہ دیگر بہت سی قیمتی صفات کے ساتھ ساتھ اس صفت سے بھی محروم ہوچکے ہیں۔ قومی زندگی کو برتر بنانے والی صفات کے ساتھ اس پر بھی غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا، حالاں کہ اس کے مختلف مظاہر کو اللہ، رسول نے دین کا درجہ دیاہے اوران کے ترک پر سخت وعیدیں ارشادفرمائی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو صرف ہمارا، ہماری قوم کا اورہماری دنیا ہی کا فائدہ نہیں بلکہ ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے ۔یہودیوں کی زندگی،مشن اورکاز کے متعلق اردو میں بھی کئی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں جن کے مطالعے سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہودی جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہر جگہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے۔قوم کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے ہی ان کی عورتیں برضاورغبت دشمنوں کے بستروں کی زینت بننا گوارا کر لیتی ہیں۔ ہم اپنے ملک کی بیٹی کو مچھلی کی طرح خود پکڑ کر عیسائیوں کے حوالے کرتے ہیں اوروہ دوسرے ملک کا ہونے کے باوجود صرف عیسائی ہونے کی وجہ اپنے لوگوں کا ہر طرح سے تحفظ کرتے ہیں اوراپنے ملک کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔اپنے ملک کے اندر شیعہ، اسماعیلی اورقادیانیوں کو دیکھ لیجیے،کیسے ان کے افراد ہرجگہ، غلط ہویادرست، اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ،اورمیں تومبنی برحق عصبیت کی بات کررہاہوں
قومی ہم دردی نہ ہونے کی وجہ سے ہی تمام اسلامی ممالک کے حکمران یا مقتدر طبقہ امیر ترین ہے اوران کے عوام غریب ترین۔اسی وجہ سے وہ قومی وملکی مفادات کا سوداکرگذرنے سے دریغ نہیں کرتے کہ انہیں اپنی قوم سے ہم دردی ہونے کی بجائے اپنے مفادات سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ قومی ہم دردی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دینے کے بجائے لینے کا معاشرہ بن گیا۔یہاں ہر شخص لٹیرا ہے،فرق صرف رسائی کا ہے ۔جس کی پہنچ جہاں تک ہے، وہ وہاں تک لوٹنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ایک ٹریفک کانسٹیبل سوپچاس روپے رشوت لیتا ہے اورایک کسٹم آفیسر لاکھوں روپے۔ دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، صرف اختیار کا فرق ہے ۔ہمارے حکمران بیرونی دوروں پر عوامی خزانے کے کروڑوں لٹادیتے ہیں اورایک عام آدمی ریل گاڑی پر بلاٹکٹ سفر کرکے انہی کی طرح قومی خزانے کونقصان پہنچاتاہے تو منشا کے اعتبار سے دونوں ہی ایک جیسے ہوئے۔ فرق یہی ہے کہ ایک کی رسائی وہاں تک ہے اوردوسرے کی یہاں تک۔آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسے شخص کو اگر اقتدار مل جائے تووہ کیا قیامت ڈھائے گا؟ ہم سب، کیا عوام کیا حکمران، ذاتی مفاد کے محافظ اورقومی مفادات کے سوداگرہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ مختلف ملتوں کے مذہبی تہوار اورایام آتے ہیں تو وہ اشیا کے نرخ کم کردیتے ہیں، حکومتیں لوگوں کو ہرممکن سہولت فراہم کرتی ہیں۔ گذشتہ دنوں مجھے ایک ایڈووکیٹ صاحب بتارہے تھے کہ میرے نواسے وغیرہ امریکہ میں ہوتے ہیں اورکئی چیزیں جو عام دنوں میں وہ نہیں خریدسکتے، ان کے لیے وہ کرسمس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رمضان آتاہے تو اشیا کے نرخ دوگنے سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی رمضان میں قیمتیں کم کرکے مسلمانوں کوسہولت دی جاتی ہے اورہم؟کیا یہ قومی ہمدردی ہے یا قوم دشمنی؟حج کے معاملے میں دیکھیں، ہندوستان میں بہت سی سہولتوں کے ساتھ کرایے پاکستان سے کم ہیں اورپاکستان میں جو کچھ ہوتاہے اورجو کچھ ہوا، وہ محتاج بیان نہیں ۔
قومی ہمدردی اورقوم دشمنی کے مختلف مظاہردیکھیں تو ان میں اصل الاصول ایک ہی بات نظر آئے گی: ذاتی مفادکو ترجیح دینا اورقوم یا فرد کے مفاد کو قربان کرنا۔ جو شخص قومی کا ہم درد ہوگا، وہ کسی موقعے پر بھی ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح نہیں دے گا۔وہ قربانی سے کام لے گا، ایثار کو اپنائے گااورذاتی مفادات کو قربان کرنا پڑا تو اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ آپ خود سے سوال کیجیے، ذاتی فائدے پر قومی مفادات کو قربان کرنے والاقوم کا ہم درد ہے یا قوم کا دشمن؟دونوں مفادات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے متعلق ہماری تاریخ میں بہت سی ’’روشن‘‘ مثالیں بکھری ہوئی ہیں۔ دور صحابہ میں اور دور تابعین میں ایسے کئی واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ پیچھے کی طرف لوٹتارہا، توں توں یہ تناسب کم ہوتا گیا۔ شریف مکہ حسین بن علی نے قوم دشمنی میں اپنا آپ انگریزوں کے حوالے کردیااورسلطان عبدالحمیدنے قومی ہمدردی میں فلسطین یہودیوں کے حوالے کرنے سے انکارکردیا۔ میرجعفراورمیرصادق جیسے کردار قوم دشمنوں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔یہی حال ہماراہے، ہم سراج الدولہ اورٹیپوکے راستے پر چلنے کے بجائے ’’میران‘‘ کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں ۔
ایک صحابی نے اپنے اہل خانہ سمیت خود بھوکارہ کرمہمان کا اکرام کیا تو اللہ نے فرمایا: ویوثرون علی انفسہم ولوکان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون۔ یہ ہے مسلمان کی شان کہ وہ خود پر دسروں کو ترجیح دیتاہے۔اللہ فرماتاہے، کامیابی اس کو ملے گی جو شح نفس سے بری ہوگا۔ آہ، افسوس کہ ہم اسی مرض میں گرفتارہیں۔قومی ہم دردی کا سبق دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحۃ، دین دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے ۔اس کا معیار کیاہے ؟ اس کو دوسری جگہ حضورہی نے بیان فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیزپسند نہ کرے جو اپنے لیے پسندکرتاہے۔اس پر مجھے ایک صحابی کا اوردوسراامام ابوحنیفہ کا ایک ایک واقعہ یاد آرہاہے کہ بائع نے انہیں قیمت کم بتائی اور انہوں نے اس کی قیمت میں خودگراں قدراضافہ کر کے مہنگے داموں اس کا سامان خریدا، کیوں کہ ان کے نزدیک مال کی صحیح قیمت یہی تھی اورخیرخواہی کا تقاضاتھاکہ درست قیمت پر مال خریدکربائع کو فائدہ پہنچایاجائے۔ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ درزی کا کام کرتے تھے اورکھوٹے سکے جانتے بوجھتے اس نیت سے لے لیاکرتے تھے کہ دینے والایہ کھوٹے سکے کہیں دوسرے مسلمانوں کونہ دے دے ۔ میاں سید اصغر حسین دیوبندی کا واقعہ لکھاہے کہ ہمیشہ برسات میں اپنے مکان کی لپائی کراتے، مگروسعت رکھنے کے باوجود اسے پختہ نہ کروایا۔ دریافت کرنے پر جواب دیاکہ اردگرد تمام اہل محلہ کے مکان کچے ہیں، میں اگر اپنامکان پختہ کرالوں گا تو یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے۔
کون سی چیز ہے جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے؟ کیا اشیاے صرف، کیا ادویات ،کیا دوسری چیزیں۔ ملاوٹ کرنے والے قوم کے دشمن ہیں یا ہم درد؟ اورجانتے بوجھتے انہیں بیچنے والوں کے متعلق کیاخیال ہے؟پھر جن کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہے ہیں اوروہ رشوت لے کر ایسے لوگوں کو عوام کی زندگی، صحت اورپیسے سے کھیلنے کی اجازت دے دیتے ہیں، وہ کس ذیل میں داخل ہوں گے ؟ابھی ذکرکی گئی حدیث کوسامنے رکھ کر سوچیں کہ کیا وہ یہ ملاوٹ شدہ اشیا اپنی ذات کے لیے پسند کریں گے؟ایسے لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں فرمایا: من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے اس کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔
اللہ فرماتاہے: إِنَّ اللّٰہَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَی أَہْلِہَا (النساء :۵۸) بے شک اللہ تمہیں حکم دیتاہے کہ تم امانتیں ان کے سپردکروجو ان کے اہل ہوں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا وسد الامرالی غیر اھلہ فانتظر الساعۃ ، جب ذمہ داریاں نااہلوں کے حوالے کردی جائیں تو بس قیامت کا اانتظار کرو۔ہم کون سا کام میرٹ پر کرتے ہیں؟ کیا رشوت لے کراور سفارش کی وجہ سے ذمہ داریوں پر ان لوگوں کا تقرر نہیں کرتے جو ان مناصب کے اہل نہیں ہوتے؟ کیا یہ قوم دشمنی ہے یا ہم دردی ؟اس قوم دشمنی میں تین لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جانتے ہیں کہ ہم اس کے اہل نہیں، پھر بھی لوگوں کا حق مار کر اوپر چڑھ آتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ان کی نااہلیت جانتے ہیں، پھر بھی ان کی شفارش کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ سب سے زیادہ مجرم ہیں جو اپنے فرض میں کوتاہی کر کے رشوت سفارش کی وجہ سے نااہل لوگوں کو عہدوں پر بٹھادیتے ہیں۔ مومن کی شان اللہ یہ بیان کرتا ہے: وَالَّذِیْنَ لَا یَشْہَدُونَ الزُّورَ (الفرقان: ۷۲) جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کیا جو لوگ جعلی ڈگریوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دے رہے؟کیا وہ امانت نااہل لوگوں کے سپردکرکے قوم سے دشمنی نہیں کررہے؟پھر یہی جعلی ڈگری ہولڈر ان عہدوں تک پہنچ جاتاہے جن کا وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ مختلف اداروں کی جو درگت بن رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ نااہل لوگ یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ایسی ڈگریاں دینے والے،لینے والے اورایسے قوم دشمن جب کسی پوسٹ پر پہنچ جائیں تو ان کی مدح سرائی کرنے والے یہ سب قوم کے دشمن ہیں نہ کہ ہم درد۔ اسی طرح وہ لوگ جو کسی فن اورفیلڈ کے نہیں، اس کو جانتے نہیں، مگر خود کو اس کا ماہر ظاہر کرتے ہیں جیسے جعلی ڈاکٹر، عطائی حکیم، نیم ملا اوربناوٹی پیر، یہ سب دھوکہ باز کرپٹ اوردشمن قوم ہیں۔ مومن کا خلق تو یہ بیان ہوا کہ وہ سیدھاسادھا بھولابھالاہوتاہے: لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکا دیتاہے نہ دھوکا کھاتاہے۔ذاتی فائدے کے لیے قوم کو دھوکا دینے والاکیا قوم کا ہم درد ہوگا؟
جس معاشرے میں قومی ہم دردی کی صفت موجودہو، وہاں دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایسامعاشرہ ضرورت مندوں کی امداد کرتاہے، محتاجوں کوسہارادیتاہے ، یتیموں اورمسکینوں کی اعانت کرتاہے ،مصیبت زدہ افراد کا ساتھ دیتاہے، مزدورکو پوری اوربروقت اجرت دیتاہے۔ وہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ حق اداکرتاہے، غصب نہیں کرتا۔ بھوکوں کوکھانا کھلاتاہے، ان کے منہ سے نوالے نہیں چھینتا۔ ننگوں کو کپڑے پہناتاہے ،ان کے تن بدن سے کپڑے نہیں اتارتا۔ کیا یہ سارے کا م وہ نہیں جن کا حکم ہمیں اللہ اوررسول نے دیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت پوراکرنے میں لگ جاتاہے، اللہ اس کی ضرورت پوراکرنے میں لگ جاتاہے۔ٹوکیومیں ابھی جو زلزلہ آیا، اس میں وہاں کے لوگوں کے رویے کے متعلق ایک کالم نگار نے کسی جاپانی عورت کا واقعہ لکھا کہ ٹوکیوسٹیشن کے باہر جس کی چھوٹی سی ایک دکان تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کی امداد کے لیے دکان کا سامان اس اعلان کے ساتھ باہر سجادیا کہ جس کے پا س پیسے ہیں، وہ دے کر لے جائے اورجس کے پاس نہیں، وہ اپنی ضرورت کی چیز ویسے ہی اٹھالے جائے۔ان غیر مسلموں کی قوم دوستی کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے تہذیبی فضلے کو تو ہم نے اپنالیا ہے، مگران کی جو چند اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں، ان سے منہ پھیرلیاہے۔ یہ صفات بھی وہ ہیں ان سے پہلے جن کا حکم ہمارے لیے خود ہمارے دین میں موجود ہے۔ ہماری قوم دوستی کاحال تویہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی حادثہ ہو، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے پہلے ان متاثرہ افراد کی جیبیں خالی کرتے ہیں، پھر انہیں طبی امداد دینے کا سوچتے ہیں۔ ادھر ہسپتالوں میں مسیحا جلادوں کاروپ دھار لیتے ہیں۔ زخمی تڑپیں،بچے بلکیں، مائیں سسکیں، بیمار چلائیں، لوگ ان مسیحاؤ ں کی غفلت پر روئیں، ان کی منت ترلے کریں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہسپتالوں میں جن مریضوں کو ٹھڈے مارتے ہیں، وہی جب ان کے ذاتی کلینک پہ چلے جاتے ہیں توجی آیاں نوں کہہ کر انہیں سرآنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ ۲۰۰۵ کے زلزلے کے بعدان علاقوں میں ایسے کئی واقعات سامنے آئے جن میں لوگوں نے اپنے بھائیوں کی امداد کرنے کے بجائے انہیں لوٹنے میں دلچسپی لی،یہاں تک کہ عورتوں کی چوڑیاں بندے حاصل کرنے کے لیے جسم کے اعضا تک کاٹ لیے ۔ہمارامعاشرہ ایک خودغرض معاشرہ ہے اورخود غرض معاشرہ کبھی قوم کا ہم دردنہیں ہوسکتا۔
مولانا اشرف علی تھانوی ایک دفعہ ٹرین میں سفر کررہے تھے۔ ایک جنٹل مین بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے قصہ چھیڑدیاکہ اسلام میں کتوں کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے، حالاں کہ اس میں یہ اور یہ خوبیاں ہیں ۔حضرت تھانوی نے شاید احادیث وغیرہ کے ذریعے سمجھایا، مگر وہ نہ سمجھا۔ آخرآپ نے فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اس میں ایک خامی ایسی ہے جو تمام خوبیوں پر بھاری ہے ۔اس نے پوچھاکون سی ؟ آپ نے جواب دیا، اس کے اندر قومی ہم دردی نہیں ہوتی۔ دیکھو جہاں کہیں کسی کتے کو ایک ہڈی ملتی ہے، دوسرے کتے آموجود ہوتے ہیں اوراس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ایک کتادوسرے کودیکھتاہے، اس پر بھونکناشروع کردیتاہے ۔اس نے کہا، ہاں یہ بات توہے ۔غور کیجیے، اپنے اخلاق کی وجہ سے کہیں ہم بھی انہی سگان آوارہ کی صف میں شامل تو نہیں ہوگئے؟
مدارس میں تصنیف و تحقیق کی صورتحال
مولانا محمد وارث مظہری
کچھ دنوں قبل ہندوستان کے ایک مایہ ناز عالم وفقیہ اور متعدداہم کتابوں کے مصنف نے راقم الحروف سے گفتگو کے دوران مدارس میں تصنیف وتالیف اور علمی تحقیق کی صورت حال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان کے سب سے بڑے اور وسیع اثرات رکھنے والے مدرسے سے متعلق کہا کہ یہاں سے گزشتہ بیس پچیس سال کی مدت میں حقیقی معنوں میں صرف دو کتابیں شائع ہوئی ہیں۔اور انھوں نے ان کتابوں کا نام بتایا۔غور وفکر کا مقام ہے کہ جب نامی گرامی اور عظیم وراثت کے امین مدرسے کی یہ حالت ہے تو دوسرے مدارس سے ہم کس طرح کوئی بڑی امید قائم کر سکتے ہیں؟اگرچہ مدارس کی سطح پر صورت حال میں تنوع پایا جاتا ہے ۔چناں چہ کہیں ٹھہراؤ کی کیفیت ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کہیں تحرک اور غور وتجزیے کی بنیاد پر تبدیلیوں کی چاپ سنائی دینے لگی ہے۔تاہم صورت حال پھر بھی بہت مایو س کن ہے۔نصاب سے قطع نظر جس پرعمومی طور پر انجماد کا پہلو غالب رہا ہے،دوسری حیثیتوں میں مدارس کی سر گرمیاں کافی نتیجہ خیز اورمؤثر رہی ہیں۔چناں چہ یہاں سے ایسے علما کی کھیپ کی کھیپ نکلی جس میں مصنفین،ادبا اورعلمی تحقیق کاروں کی بڑی تعداد شامل تھی۔انھوں نے اپنے پیچھے اہم علمی اثاثہ چھوڑا،جو موجودہ و آئندہ نسلوں کے لیے فکر وبصیرت کا سامان ہیں۔زیادہ پیچھے کی طرف نہ لوٹتے ہوئے آزادی کے بعددو تین دہائیوں تک علوم و افکا ر کے میدان میں سامنے آنے والی اور مدارس سے انتساب رکھنے والی شخصیات کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو وہ طویل ہونے کے ساتھ ساتھ کافی باوزن دکھائی دیتی ہے۔
لیکن آج کی صورت حال نہایت افسوس ناک ہے۔اکثرمدارس پر صرف نصابی سرگرمیاں حاوی ہیں۔غیر نصابی سر گرمیوں کا دائرہ نمایاں طور پر تقریر کی مشق تک محدود ہے۔نتیجے کے طور پر مدارس سے غالب تعداد میںیا تو مدرسین پیدا ہو رہے ہیں یا مقررین یا پھر اسی درس و تقریر کی مشق کرنے کرانے والے شارحین وتقریر نگار۔ان کے علاوہ ایک تعداد مسلکی اور گروہی چپقلش پر خامہ فرسائی کرنے والوں کی ہے۔دوسرے موضوعات کے لیے جو تعداد بچتی ہے وہ نہایت قلیل ہے اور اس میں بھی اقل وہ تعداد ہے جو سنجیدہ ،علمی اسلوب میں علمی تحقیق وتصنیف کا کام کر رہی ہو۔حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی کئی دہائیوں سے حدیث،تفسیر اور فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والی شخصیات، مدارس کی دنیا میں جن کے نام کا سکہ چلتا ہے،وہ بھی ابتدائی درسی کتابوں کی شرح و حاشیہ نگاری کوممتاز علمی وتصنیفی کام تصور کر بیٹھی ہیں۔ان کے ممتاز تلامذہ کا حلقہ انھیں یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ یہ’لاثانی‘اور’لافانی‘ کا م انھی کا خاصہ ہے۔اوریجنیلٹی،تخلیقی فکر اور تازہ کاری جو موجودہ علمی سرمایے میں اضافے کا باعث ہو اور جس سے قافلہ علم کوآگے بڑھنے کے لیے توانائی حاصل ہو،ایسا کام اب مدارس سے نکل کر جدید علمی دانش گاہوں،علمی اکیڈمیوں(اپنی محدودیتوں کے باوجود) میں اچھے اور بڑے پیمانے پر انجام پا رہا ہے۔نہ صرف ہندوستان میں بلکہ واضح طور پربر صغیر کے تینوں ممالک میں۔مثال کے طور پر تمام تر حلقے شاہ ولی اللہ سے اپنی نسبت قائم کر نے پر نازاں ہیں،لیکن مدارس کے حلقوں میں حجۃ اللہ البالغہ کے علاوہ، جو خال خال بعض جگہوں پر پائی جاسکے،بہ مشکل ہی کوئی اور کتاب پڑھی اور شائع کی جاتی ہے۔حالیہ مدت میں شاہ صاحب پر سیمینار علی گڑھ اور دہلی میں ہورہا ہے نہ کہ دیوبند ا ور ندوہ میں۔ اسی طرح مثال کے طور پر دہلی میں مکتبہ اسلامی، آئی او ایس اور اسلامی مرکز سے جس طرح کی علمی ،فکری اور تحقیقی کتابیں چھپ کرآئی ہیں ،مدارس سے وابستہ یا ان کے زیر اثر قائم نشریاتی اداروں کی فہرست میں ایسی کتابیں محض استثنا ہیں۔کتابوں کی اشاعت کے علاوہ یہی صورت حال مدارس سے شائع ہونے والے رسائل و مجلات کا ہے۔اداریہ سے لے کر اختتامیہ تک اکثر رسائل و مجلات محض عوام کے تیسرے اور چوتھے صف کے لوگوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔بالکل وہی کام جو مجلسی ملفوظات اور اسٹیج کی تقریروں سے لیا جا سکتا ہے،ان پرچوں سے لیاجاتا ہے۔بہر حال یہ ایک دل چسپ مطالعے کا موضوع ہے،ارشد امان اللہ نے اس موضوع (مدرسی صحافت) کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے،جس کے نتائج سرائے ڈاٹ نیٹ کی سائٹ پر موجودہیں۔مدارس کے حلقوں سے جن موضوعات پر کتابیں چھپ رہی ہیں ان کے سرسری جائزے سے جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے:
- درسیات و متعلقات درسیات
60-65 فیصد - دینیات: ( فتاوی و احکام، اصلاح و تبلیغ ، تذکرہ و سیرت)
15-17 فیصد - وعظ و تقریر، ملفوظات و مکتوبات
10-12 فیصد - مسلکی تنازعات ، تعویذات و عملیات
9-10 فیصد - علمی و تحقیقی کتابیں (بہ مشکل)
1 فیصد - متفرقات
3-4 فیصد
یہ جائزہ مدارس کے حلقوں خصوصاً دیوبند میں چھپنے والی کتابوں کی تمام بڑی اور اہم فہرستوں کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ اس میں بعض چھوٹے موضوعات کو بڑے موضوعات جیسے تصوف کو ملفوظات و مکتوبات اور سیرت کو اصلاح و تبلیغ، لغات وغیرہ کو متعلقات درسیات میں شمارکر لیا گیا ہے۔ اس طرح باقی دوسرے موضوعات متفرقات کے ذیل میں ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ دیوبند دینی کتابوں کا ہندوستان میں سب سے بڑا مرکز ہے اور مدارس کے حلقوں کا نمائندہ ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں یہاں سے دینی ، درسی کتابیں پہنچتی ہیں۔اگرچہ میرے خیال میں ہندوستان میں پھیلے مدارس کے اہم حلقوں: دارالعلوم ندوۃ العلماء ، مدرسۃ الاصلاح اور جامعۃ الفلاح، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث، اہل تشیع وغیرہ کی نشریات و مطبوعات کابھی جائزہ لیا جانا چاہیے ، تاکہ علمی و فکری سرگرمیوں اور اکیڈمک ارتقا کا زیادہ ہمہ گیری اور صحت کے ساتھ اندازہ ہو سکے۔
میری نظر میں اس صورت حال کے متعدد اسباب ہیں:
- بنیادی سبب مطمح نظر کی محدودیت ہے۔در اصل مدارس کے ارباب حل وعقد نے مدارس کے مقاصد کو محض چند امور تک محدود کر دیا ہے یعنی:روز مرہ کے مذہبی مسائل میں عوام کی رہنمائی اور روایتی حدود و قیود کے ساتھ اسلامی ثقافت کے مظہر کوسماجی سطح پر محفوظ و برقراررکھنے کی کوشش کرنا۔لیکن سوال یہ کہ اس کے لیے آٹھ سال کے عرصے میں دس سے زائد علوم کی تحصیل کی ضرورت کیا ہے؟ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے روز مرہ کے شرعی مسائل کی ضروری واقفیت کے ساتھ دو تین سال کی دینی تربیت کافی ہے۔علمائے دیوبند میں مولانا تھانوی کا نقطۂ نظر یہی تھا۔ ان کی نظر میں عالم ومحقق اور دینی مسائل کی واقفیت اور دینی تربیت رکھنے والوں کے مابین پائے جانے والے فرق کی حقیقت واضح تھی۔
- مدارس اوردوسرے فکری و علمی حلقوں کے درمیان کوئی باضابطہ رشتہ اور تال میل قائم نہ ہو سکا۔اس کے بر عکس دونوں اداروں میں چپقلش کی فضا قائم ہوگئی جس میں دونوں ہی اداروں کی کمزوریاں شامل ہیں۔ البتہ ارباب مدارس کی طرف سے دینی و دنیاوی علوم کے تصور نے اس تفریق اور دوری میں خصوصی کر دار ادا کیا۔
- مدارس مخصوص خانوادوں میں سمٹ کر رہ گئے یا دوسرے لفظوں میں ان پرمخصوص خاندانوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔یہ ام الامراض ہے جس نے مدارس کو مختلف حیثیتوں سے جن میں:مدارس میں جمہوریت کا فقدان،ان کے نظام اور سرگرمیوں پر کار وباریت کی چھاپ،ملازمین کا استحصال وغیرہ، اہم ہیں، کمزور و بے جان کر دیا۔’ اہتمام کی گدی نشینی ‘کر نے والوں نے نشر واشاعت کے حوالے سے اپنی ساری توجہ اپنے آبا واجداد کے کارناموں کواجاگر کرنے پر صرف کر دی۔چناں چہ انھی کی سوانح و تذکرے،خطبات وملفوظات،تصنیفات و تالیفات شائع ہونے لگیں اور انھی پر علمی نشستوں اور سیمیناروں کا انعقاد ہونے لگا۔
- نصاب کی محدودیت کی وجہ سے ہمارے علما مدارس کی چہار دیواری میں سمٹتے چلے گئے۔اس طرح سماجی تبدیلیوں سے بے خبری کے ساتھ علوم وافکار کے میدانوں میں ہونے والی حالیہ پیش رفت سے وہ مکمل طور پر نا آشنا رہے۔
- محنت اور صلاحیت سے متصف لوگوں کے لیے معاشی مسائل ان کے پاؤوں کی زنجیر بن گئے۔بے صلاحیت مقررین اسٹیج کی تقریروں کے ذریعے اعزازیے اور تحائف وصول کرنے لگے تو ان لوگوں نے طلبہ کواپنی تدریس سے زیادہ اپنی مطبوعہ شروحات کی طرف متوجہ کیا اور اس طرح پہلے طبقے کی برابری کی کوشش کی۔اب حقیقی معنوں میں ان درسی کتابوں کی شروحات لکھنے والوں اور کتابوں کے ناشرین میں جیسے ایک دیدہ یا نادیدہ ساز باز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔بعض نصابی کتابوں کی خامیاں پوری طرح ارباب حل و عقد کی نگاہوں میں واضح ہو جانے اور نئی کتب کی شکل میں بہتر سے بہتر متبادل آجانے کے باوجود وہ انھیں درس سے اس لیے خارج کر نے سے قاصر ہیں کہ وہ ان دونوں طبقات کے اعتراضات و تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے۔مختلف صورتوں میں ان کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔
- مدارس میں یا تو سرے سے تصنیف و تحقیق کا کوئی شعبہ نہیں ہے یا اگر ہے تو اسے لائق وفاضل افراد مشکل سے میسر آتے ہیں۔اس کی وجہ مدارس کا وہ بند ماحول ہے جس میں تخلیقی فکر رکھنے والے اہل قلم کے لیے خود کو ایڈ جسٹ کر نا آسان نہیں ہوتا۔
- اس گراوٹ کی ایک وجہ فضلا ئے مدارس کی اکثریت کا ایک زبان (شمالی ہند کے تناظر میں اردو)پر انحصار اور عالمی مغربی زبانوں اور خود عربی سے عدم واقفیت ہے۔زبان کے تعلق سے عربی پوری طرح موجودہ علمی تقاضوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تاہم اس سے ایک حد تک اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے جو اردو کے تعلق سے موجود ہے۔حقیقت یہ ہے کہ عربی موجودہ دور میں اردو سے زیادہ ’جمہوری‘ اور ’سیکولر‘ہے۔ اردو بنیادی طور پرشمالی ہند کے مسلم معاشرے کی روحانی زبان ہو کر رہ گئی ہے۔آپ ایسی باتیں تلخ وترش تنقید برداشت کیے بغیرمشکل سے ہی لکھ سکتے ہیں،جواہل مدارس کے مزاج اور انداز کے مطابق نہ ہوں۔
- علمی تحقیق و تصنیف کابڑا اور وسیع کام صرف افراد کے ذاتی شوق و جذبے کی بنیاد پر ہی انجام نہیں دیا جا سکتا۔ زیادہ بہتر طورپروہ علمی پروجیکٹوں کی شکل میں انجام دیا جاتا ہے۔ ماضی میں امرا اور شاہوں کی عطیات نے بہت سی چھپی دبی صلاحیتوں کو ضخیم کتابوں کی شکل میں منتقل ہونے کا موقع دیا۔ آج مغربی دنیا میں اس مقصد کے لیے بڑے بڑے ادارے: کارنیگی فاؤنڈیشن ، فورڈ فاؤنڈیشن، فل برائٹ وغیرہ موجود ہیں جو علمی تحقیقی کاموں کو باضابطہ پروجیکٹوں کی شکل میں انجام دیے جانے کے لیے ضروری وسائل فراہم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اس قسم کے ادارے تقریباً معدوم ہیں۔ مدارس کی بڑی تعداد کے لیے سالانہ بجٹ کی فراہمی ہی ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ تاہم بڑے مدارس جن کا سالانہ بجٹ کروڑوں میں ہے، کم از کم اپنے فاضلین کو علمی پروجیکٹوں میں مصروف کرنے کے لیے بجٹ کا ایک حصہ مختص کر سکتے ہیں۔
مدارس کے حلقوں میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق علمی دانشمندی ( اسکالر شپ) کے فروغ اور فاضلین مدارس اور علما میں اکیڈمک ریسرچ کا صحیح شعور بیدار کرنے کے لیے منصوبہ بند اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان اقدامات میں سے چند ضروری اور فوری اقدامات یہ ہیں:
- مدارس کے مجموعی ماحول کو اس طرح ترتیب دینا کہ مدارس کی نئی نسل کا صرف کتاب پڑھنے پڑھانے پر ہی انحصار نہ ہو اور وہ صرف اس کی ہی اہمیت سے واقف نہ ہو۔بلکہ یہ بات اس کے شعور کا حصہ بن سکے کہ مطالعہ کا مقصد محض علم کے دائرے کو وسیع کرنا اور ترقی دینا نہیں بلکہ فکر کے دائرے کو بھی وسیع کرنااور اسے ترقی دینا ہے۔
- علم کے لیے جس تجسس(Curiosity) اور تازہ کاری کے لیے جس تخلیقی فکر کی ضرورت ہے وہ حقیقت میں مدارس میں رائج نصاب سے حاصل نہیں ہوتی۔ مدارس کے نصاب میں سوشل اسٹڈیز اور زبان کی سطح پر خصوصی تبدیلی و اصلاح کی ضرورت ہے۔ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے مدارس کو آسانی کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتاہے، جدید تعلیمی پالیسی میں حکومت ہند کی اس طرف خصوصی توجہ ہے۔ اپنے بعض تحفظات کے ساتھ مدارس کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے ۔ تاکہ طالب علم کے مطالعہ و مشاہدے کا دائرہ وسیع ہو۔ زبان کے تعلق سے انگریزی کو باضابطہ نصاب کے اصل دھارے میں شامل کرنے اور ہر ہر طالب علم کے لیے کم و بیش میٹرک کی سطح تک کی انگریزی زبان کی واقفیت کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ آج کی ضروریات اور تقاضوں کو کل کے اکابر و اسلاف سے مقابلہ (Compare)کر کے دیکھا نہیں جاسکتا۔
- دینی اور دنیاوی علوم کی تفریق کے خاتمے کے ساتھ مدارس کے نصاب میں ’’ قدیم صالح‘‘ اور ’’ جدید نافع‘‘ کے امتزاج و شمولیت سے جب تک مدارس کے نصاب میں توازن پیدا نہیں ہو جاتا، اس صورتحال میں کوئی خوشگوار تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کی فکرکے مطابق ، مدارس کے فضلا کے لیے یونیورسٹیوں میں داخلے کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ جنوبی ہند کے بہت سے اہم دینی ادارے اس کی نمایاں مثال ہیں۔
- تمام بڑے مدارس میں تحقیقی اکیڈمیاں اور مراکز قائم کی جائیں۔ بعض مدارس میں ایسے مراکز محض دکھاوے کے لیے ہیں۔ ان سے زیادہ سے زیادہ ادارے کے بانیان و اکابر کی یا ان سے متعلق ،اور دوسری صورت میں گروہی چپقلش پر مبنی مواد شائع کیے جاتے ہیں۔ اس طرح علم کی یہ آواز یا تو اپنی ہی چہار دیواری میں گونج کر رہ جاتی ہے یا پھر وہ اتنی بھونڈی ہوتی ہے کہ اس چہار دیواری سے باہر اس کو سننے والا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔
- اس مقصد کے حصول کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں میں مختلف چیزوں پر توجہ اور ارتکازکی ضرورت ہے۔ جیسے: ماہرین اصحاب علم کے ذریعہ ہفتہ وار، پندرہ روزہ یا ماہانہ محاضرے کا پروگرام، تقریری مجالس کی طرح تحریری مقابلوں کا پروگرام، مختلف موضوعات پر اوپن ڈسکشن کا اہتمام و انتظام، ملک اور ملک سے باہر مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے اہم رسائل و مجلات کی کٹیلاگ سازی اور طلبہ کو ان کی فراہمی، مرکزی لائبریری میں ضروری بنیادی کتابوں کے ساتھ نئی شائع ہو کر منظر عام پر آنے والی کتابوں کا ذخیرہ جن سے طلبہ بہ آسانی اور بر وقت استفادہ کر سکیں۔ اس طرح طلبہ میں تحریری ذوق کو ابھارنے کے لیے سالانہ سطح پر طلبہ کی تحریری کوششوں پر انعامات دینے کے علاوہ ان پر بھی نمبرات دیے جانے چاہئیں اور انہیں سالانہ مارک شیٹ میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔
- طلبہ کی تحریری و صحافتی تربیت کے لیے مدارس میں باضابطہ اس کے شعبے اور تربیتی مراکز (Training Centers) کھولنے کی ضرورت ہے۔
- دیواری رسائل کے علاوہ طلبہ کے لیے مختص با ضابطہ طبع ہونے والے رسائل بھی ہونے چاہئیں، جن میں ان کی تخلیقات شائع ہوں، پھر ان کی منتخب تحریروں کو کتابی شکل میں شائع کیا جانا چاہئے۔
- اخیر کے دو سالوں میں بالترتیب ہر سال میں کم از کم 50اور 100صفحات پر مشتمل تحقیقی مقالہ (dissertation) طلبہ سے لکھوایا جانا چاہیے اور ان پر حاصل ہونے والے نمبرات کو سالانہ امتحان کے مجموعی نمبرات میں شامل کیا جانا چاہیے۔
- تمام بڑے مدارس میں کم از کم سال میں ایک مرتبہ کسی اہم اجتماعی دلچسپی کے حامل موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ اس میں اہم علما اور دانشوروں کے علاوہ قدیم با صلاحیت فضلا کو مدعو کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ کی نئی نسل ان سے سیکھ سکے اور ان کے نقش راہ کو اپنانے کی کوشش کر سکے۔
- ہمارے بڑے مدارس کا خاص طورپر عالم اسلام کی بڑی جامعات کے ساتھ باضابطہ ربط اور معادلہ ہونا چاہیے جس کے تحت یہاں کے طلبہ وہاں اور وہاں کے طلبہ یہاں آکر دونوں جگہوں کے تعلیمی نظام و نصاب سے اپنی ضرورت کے مطابق استفادہ کر سکیں۔ اس کے لیے ’’ عالم اسلام‘‘ کی قید بھی بے جا ہے۔ ہمیں با صلاحیت، منتخب ، پختہ اسلامی فکر رکھنے والے طلبہ کے لیے یہ رسک لینا چاہیے کہ انہیں ضروری تربیت کے بعد مغرب کی اعلیٰ دانش گاہوں کے مذہبی مطالعات کے شعبوں میں داخل کرایا جائے۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ادارہ مستقل طورپر ان کے ساتھ ربط اور ان پر نگاہ رکھے اور انہیں ضروری تعاون فراہم کرے۔ اس بھٹی میں تپنے کے بعد وہ موجودہ عالمی تقاضوں کے مطابق زیادہ کار آمد ہو سکیں گے۔ جامعہ ازہر کا پیٹرن یہی ہے ازہر کی طرف سے بھیجے گئے ایسے اسلامی علم و ثقافت کے سفرا مغربی ممالک کی تاریک فضا میں اسلامی علم و ثقافت کو پروان چڑھانے میں مصروف ہیں۔ پچھلے دنوں ازہر کے ایسے کئی نمائندوں پر مغربی ملکوں میں حملے ہوئے لیکن اس کے جواب میں ازہر نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ اپنے نمائندوں کو اسی طرح وہاں بھیجتی رہے گی۔ بلا شبہ یہ زیادہ بڑا اقدامی کام ہے جس کے لیے بہت زیادہ تیاری اور ہمت جٹانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے بعض مرکزی ادارے مکہ و مدینہ کی علمی درسگاہوں سے بھی اس لیے معادلے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہاں جا کر فضلا کی حنفیت اور گروہی مسلکیت کی بند ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اس ذہنیت کا جس قدر بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔
یہ اور اس طرح کے اقدامات اور کوششوں کے ذریعہ مدارس کے اندر اسلامی اسکالر شپ کے گرتے ہوئے معیار کا علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ مدارس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی خود اطمینانی (self-sufficiency) کی یہ ذہنیت ہے کہ مدارس میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی نہیں اعلیٰ معیار کے مطابق ہے۔ اس لیے ان سے اس سے اوپر کی توقع کرنا غلط اور بے جاہے۔ یہ ذہنیت علم میں اضافے اور فکر میں نمو کے لیے تجسس و اضطراب کی اسپرٹ کو ختم کر دیتی ہے۔
بہر حال مدارس میں علم و تحقیق کے معیار کی گراوٹ (slow down) وقتی نہیں ہے کہ اس کے علاج کے لیے کوئی فوری 'bail out' پروگرام یا پیکیج تیار کر لیا جائے۔ اس کے لیے مدارس کے پورے نصاب و نظام کے حقیقت پسندانہ اور معروضی جائزے کے ساتھ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ تبھی یہ مدارس عام درسگاہوں کی طرح محض پیشہ ورانہ انداز میں پڑھنے پڑھانے والے ادارے کی حیثیت سے اوپر اٹھ کرحقیقی معنوں میں علم و فضیلت (scholar ship)اور فکر و تحقیق کے اعلیٰ اور اساسی اداروں کی حیثیت سے موجودہ دور کی نمائندگی اور مسلم و غیر مسلم سماج پر اپنے اثرات قائم کر سکنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ ورنہ دوسری صورت میں بہر حال اقبال کی یہ شکایت اسی طرح باقی رہے گی کہ:
نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ
عصر حاضر میں غلبۂ اسلام کے لیے جہاد
اویس پاشا قرنی
’’اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے غلبہ چاہتا ہے‘‘۔ ماجرا کچھ یوں ہے کہ یہ فقرہ آج ایک خاص تصورِ دین کا عکاس ہے۔ اِس عبارت کو سمجھنے کے لیے گزشتہ صدی کے فکری رجحانات اور ان کے اظہار کے لیے وضع کردہ خاص محاورے اور اصطلاحات کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نسل انسانی کے اجتماعی شعور نے جب اپنے گزشتہ مشاہدات و تجربات کی روشنی میں اپنی اجتماعیت کو ایک مربوط نظام کی شکل دینے کی کوشش کی اور اِس کی پشت پر افراط و تفریط پر مبنی خالص مادی نقطۂ نظر سے مختلف فکری استدلال بھی قائم کیے‘ تو بالکل فطری تقاضے کے طور پر مسلمان اہل علم نے دین اسلام کی’’ تعبیر ‘‘ وقت کے محاورے اور اصطلاح کو سامنے رکھتے ہوئے کی۔ یہ اِسی کا مظہر ہے کہ آج ہم اپنی روز مرہ کی زبان میں اِس جیسے کئی جملے استعمال کرتے ہیں کہ ’’ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے‘ اسلام کا معاشرتی نظام‘ سماجی نظام‘ معاشی نظام‘ سیاسی نظام وغیرہ‘‘۔اِس تعبیر کے ساتھ جو ایک خاص جذبہ کار فرما تھا اُسے خود شعوری یا احساسِ بیداری کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس عام ہوا کہ نظاموں کی اس کشاکش کے درمیان ‘ جبکہ ہر قوم اپنے افراط و تفریط پر مبنی مادی ‘ خدابے زار نظامِ حیات کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتی ہے‘ ہم بھی ایک نظامِ حیات کے دعوے دار ہیں‘ جس کی ترتیب و تدوین وحی و رسالت کے ہاتھوں ہوئی ہے اور اِسی پر عمل پیرا ہو کرہم نے اِس دنیا پر کئی صدیوں تک حکومت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اِسی فکری و نظری لہر کے نتیجے میں تمام بلادِاسلامیہ میں مختلف تحریکات غلبہ و اقامت دین یا اسلام کی نشاۃِ ثانیہ کی آرزو کے ساتھ میدانِ عمل میں اُترتی ہیں۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب اُمت مسلمہ کے فکری قائدین نے اِس قافلہ کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور اس طرح احیاءِ اسلام کا عمل جاری ہوا ۔
ان احیائی تحریکوں میں ایک نئے عنصر کا ظہور ماضی قریب میں ہوا ہے۔ غلبہ و اقامت دین کے لیے کام کرنے والی ان تحریکات پر قریب قریب ایک صدی مکمل ہونے کو ہے مگر واقعاتی دنیا میں کوئی قابل ذکر تبدیلی رونمانہیں ہوئی ‘یعنی جو نتائج مطلوب تھے وہ حاصل نہیں ہوئے ‘اِلاّ یہ کہ کچھ صالحین مسلم معاشروں میں سے ان تحریکات کے عنوان سے مجتمع ہو گئے۔ان نتائج کے سامنے آنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے کام پر ناقدانہ نگاہ ڈالتے اور خامیوں ‘کوتاہیوں کا ازالہ کرتے ہوئے مستقبل کے لیے خوداحتسابی کے ساتھ پرجوش انداز میں سرگرم عمل رہتے ۔مگر بدقسمتی سے انسان جلدباز واقع ہوا ہے ۔نیا منظر نامہ یوں مرتب ہوا کہ ان تحریکات کے کچھ پرجوش اور سرگرم عناصر اپنے گزشتہ سوچے سمجھے‘ معتدل اور محتاط طریقہ کارکے بارے میں نا امیدی اورشکوک وشبہات کا شکار ہو گئے ‘جیسا کہ فکری خلا کا کوئی وجود نہیں اور انسان کسی صحیح یا غلط استدلال کے اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ چنانچہ ان عناصر نے جلدبازی میں ایک نئی راہ اختیار کی جو کہ ہمہ گیر اسلامی تحریک کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہے۔اس ہنگامی صورت حال سے قبل عالمِ اسلام میں احیائی عمل کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ پہلے دعوتِ ایمانِ حقیقی‘ تزکیۂ نفوس‘ تعلیم کتاب وحکمت‘ تربیت وتنظیم‘ پھر جہاد وقتال۔ جبکہ اس جدید استدلال میں بات تکفیر سے شروع ہوتی ہے اور مجہول الہدف‘ بے نتیجہ قتال کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس بے اصل استدلال کو شرعی نصوص سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان صفحات میں ہمارے پیش نظر اسی اشکال کا جائزہ لینا ہے ۔
اِس امر میں تو مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ چاہے معاملات ہو ںیا عبادات‘ معاشرت ہو یا سیاست و ریاست‘ عملی رہنمائی کا اصل ماخذ قرآن کریم اور رسول اللہﷺ اورخلفائے راشدینؓ کی سنت و سیرت ہے۔ جس طرح یہ اصول دیگر دینی تعلیمات کے لیے صحیح ہے اِسی طرح غلبہ و اقامتِ دین یا نصبِ امامت و خلافت کے طریقہ کار ‘ لائحہ عمل اور منہج انقلاب کے اخذ کرنے کا اولین و اہم ترین ذریعہ بھی سیرتِ رسول ﷺ ہے۔ (اس فرق کے ساتھ کہ عبادات یعنی تعبدی اُمور میں اصل ’’حرمت‘‘ ہے یہاں تک کہ اُس کی حلت ثابت ہو جائے اور معاملات میں اصل ’’اباحت ‘‘ہے یہاں تک کہ اُس کی حرمت ثابت ہوجائے۔) معلوم یہ ہوا کہ مصدر و ماخذ سے متعلق کوئی اختلاف نہیں‘ بلکہ یہ جو تنوع ہم تحریکوں کے طریقہ کار میں پاتے ہیں یہ اصلاً اُس کے فہم اور تعبیر و تشریح میں نقطۂ نظر کی صحت و ضعف کا ہے۔واضح رہے کہ جب ہم کسی فعل کے لیے کسی واقعہ سے نظیرلیتے ہیں یا قضیۂ اولیٰ کو قضیۂ ثانیہ پر قیاس کرتے ہیں تو اِس امر کی صحت و بطلان کا انحصار دو اساسات پر ہوتا ہے‘ جسے اصولیین کی زبان میں اصل اور فرع یا مقیس علیہ اورمقیس کہتے ہیں۔ جب تک ہر دو اجزاء کی مکمل معرفت ‘ اُن کے اوصاف و خواص‘ تعمیم و تخصیص ‘ اطلاق و تقیید سے واقفیت اور سبب و علت پر حکیمانہ نظر نہ ہو تو یہ استشہا د خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔
زیر نظر موضوع پر جب ہم اِس اصول کی روشنی میں غور کرتے ہیں تو تعقل کے اجزا یہ قرار پاتے ہیں:
(۱) منہج انقلاب اخذ کرنے کے نقطۂ نظر سے رسول اللہ ﷺ کی سیرتِ مطہرہ کامطالعہ ۔
(۲) موجودہ احوال و ظروف کا دقتِ نظر ی سے مطالعہ۔
جزوِ اول کی حیثیت اصل یا مقیس علیہ کی ہو گی اور جزوثانی فرع یا مقیس کہلائے گا ۔ اِس بات میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں اجزاء اپنی انفراد ی حیثیت میں مکمل توجہ کے مستحق ہیں ‘کوئی بھی جزو ثانوی درجہ کا نہیں ‘اس لیے کہ مطلوبہ مقاصد کا حصول صرف اُسی وقت ممکن ہے جب دونوں اجزاء کی صحیح معرفت ہو۔ یعنی سیرت کے مطالعے میں خاص معروضی نقطۂ نگاہ کو اپنایا گیا ہو جو کہ تخریج منہج کے لیے مطلوب ہے۔ اور اِسی طرح اپنے زمانہ کے مزاج ‘ تقاضے‘ دورِ نبویؐ کے مقابلہ میں رو نما ہونے والے فرق و تفاوت ‘ تمدنی و فکری ارتقاء اور دیگر قابل لحاظ امور کی صحیح صحیح تحقیق و تنقیح کر لی گئی ہو۔ فقہ کی اصطلاح میں پہلے جزو کو فقہ الاحکام اور دوسرے جزو کو فقہ الواقع سے تعبیر کیا جاتاہے اور ایک شخص کے لیے دونوں اجزا کی تحقیق لازم ہے، ورنہ وہ مقاصدِ شرعیہ کی من کل الوجوہ پاسداری نہیں کر سکتا۔
اِس کو عام فہم انداز میں اِس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک کاریگر فرمے یا سانچے سے کوئی شے تیار کرتا ہے۔ اِس عمل کے دو اجزاء ہیں ‘ایک سانچہ اور دوسرا وہ مادّہ جس کو اُس سانچے میں رکھ کر مطلوبہ شے تیار کی جاتی ہے۔ کاریگر کا دونوں اجزاء سے اچھی طرح واقف ہونا یکساں طور پر ضروری ہے۔ اُسے فرمے یا سانچے کا استعمال بھی آتا ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو کہ جس مادہ کو سانچہ میں ڈالا جاتا ہے اُسے پگھلا کر استعمال کیا جاتا ہے یا کاٹ کر یا پیس کر۔ مطلوبہ شے کا حصول تبھی ممکن ہے کہ جب کار یگر دونوں اجزاء سے گہری واقفیت رکھتا ہو۔
اللہ عزوجل نے اپنے نبی حضرت محمدﷺ کو اظہارِ دین یا اقامت دین کے لیے جو منہج دے کر بھیجا وہ واضح طور پر دو مراحل میں منقسم ہے‘اور ہر دو مراحل اپنی نوعیت ‘اثرات اور تقاضوں کے اعتبار سے مختلف اور متضاد بھی ہیں ۔ اگر مکی دور میں نازل ہونے والی آیات پر ایک سر سری نگاہ ڈالی جائے تو کوئی مانع نہیں جو اِس تأثر کے اخذ کرنے سے ہمیں روکتا ہو کہ اُس دَور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبیؐ‘ کوجو منہج اور طریقۂ کار دیا گیا تھا وہ دعوت اور تبلیغ ہی کا تھا جس میں ایک خاص درویشانہ رنگ غالب ہے۔ یہ دَور جہادو قتال سے یکسر خالی ہے۔ اور اگر کہیں آیات میں لفظ جہاد استعمال ہوا ہے تو اُس کے معنی کوشش اور جدوجہد کے ہیں نہ کہ جنگ و قتال کے۔ اُس دَور کی کیفیا ت کا مطالعہ کیا جائے توچند عناصر بہت واضح ہیں‘ جیسے یہ حکم کہ صبر کیے جاؤ ‘یعنی جو مصائب دعوت کے دوران پیش آئیں اُن پر صبر کی تلقین ہو رہی ہے۔ استقامت یعنی اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہر مصیبت کو جھیل جانے کا عزم پیدا کیا جا رہا ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیے جانے پر اُبھارا جا رہا ہے‘ تزکیۂ نفوس پر زور ہے‘ نماز اپنی ابتدائی شکل میں ہے اور اُس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اخلاق کی تہذیب مطلوب ہے۔ حق بات کہنے پر جو ذہنی یا جسمانی اذیت پہنچے اُس پر کمالِ استقامت کی ترغیب اور اس کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ایمان و تقویٰ میں درجۂ احسان کی جانب پیش قدمی کے لیے تحریض و تشویق ہے۔ سیرتِ نبویؐ کے اس مرحلہ میں مسلمانوں کی پوری جماعت کو اِس بات کی سخت تاکید تھی کہ ظلم کے جواب میں کوئی اقدام نہیں کرنا ۔ یعنی مار کھانا ہے مارنا نہیں ہے‘ جان دینا ہے جان لینا نہیں ہے۔ اِسی حکم کو بعد میں اِن الفاظ میں ظاہر کیا گیا:
( اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ قِیْلَ لَہُمْ کُفُّوْآ اَیْدِیَکُمْ ۔۔۔) (النساء :۷۷ )
’’کیا تم نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔۔۔؟‘‘
مکی دَور کے منہج کے بر عکس ہجرت کے بعد یعنی مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا عناصر میں چند اور چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے جس سے جد وجہد کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اب کفار کو نہ صرف اُن کے ظلم کا جواب دیا جا رہا ہے‘ بلکہ آگے بڑھ کر چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ اُن سے دو بدو جنگ ہو رہی ہے‘ اُن کی گردنیں اُتاری جا رہی ہیں‘ کفار و مشرکین کو قیدی بنایا جا رہا ہے۔ جہاں معاہدہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں عہد و میثاق ہو رہے ہیں ‘جہاں عارضی صلح درکار ہے وہاں امن و صلح کی بات چیت ہو رہی ہے۔ غرض اس اُبھرتی ہوئی طاقت کے لیے جس وقت جو عمل مناسب ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے‘ یہاں تک کہ اللہ عزو جل نے اسلام کو شان و شوکت سے نواز دیا۔ ہر دو مراحل کے تقاضے یکسر مختلف ہیں۔ بظاہر یہ تضاد ہے مگر حکمت دین کو محلوظ رکھتے ہوئے اگر سیرت کے اِن اَدوار پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان مراحل کے مابین نسبت تضاد کی نہیں بلکہ تدریج کی ہے۔ ایک مقدم ہے اور ایک مؤخر!
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولﷺ کو غلبہ و اقامت دین کے لیے جو منہج دے کر بھیجا وہ واضح طور پر دو مرحلوں پر منقسم ہے‘ جیسا کہ قرآن و سیرت کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔ ایک کو ہم مکی دَور کہتے ہیں اور ایک کو مدنی دَور۔ ان کے مابین اصل فرق یہ ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کی تعداد اور استعداد کم تھی‘ ان کی تربیت اور تزکیہ و تنظیم کا عمل جاری تھا اِس لیے رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ‘ کو حکم یہ تھا کہ اسلام کی دعوت اپنے قول و فعل سے دیتے رہیں۔ ایمان کی پختگی ‘گہرائی اور گیرائی کے لیے سعئ پیہم جاری تھی۔ اخلاق کی تہذیب‘اللہ کے ساتھ عبدیت کے تعلق کو مستحکم کرنے کی کوشش اور درجۂ احسان کا حصول اُس دَور میں اپنے عروج پر نظر آتا ہے ۔منہج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صبح وشام اُس مطلوبہ استعداد اور تعداد کو حاصل کرنے کے لیے دعوت کا عمل ہر قربانی اور ایثار کے جذبہ کے ساتھ انتہائی مستقل مزاجی اور بغیر کسی مدا ہنت کے جاری و ساری تھا۔ یہی وہ تشکیلی دَور ہے جس میں رسولِ خداﷺ نے وحئ الٰہی کی روشنی میں صحابہ کرامؓ ‘کی صورت میں وہ قوت و جمعیت فراہم کی جو کسی بھی نظام سے ٹکرانے یا بالفاظِ دیگر مسلح یا غیر مسلح اقدام کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں نبی اکرمﷺ اور ان کے صحابہؓ مشرکین کے مظالم کے جواب میں صبرو مصابرت کی روش پرگامزن ہیں اور اس کے بر عکس مدینے میں ایک ایسا وقت بھی آیاکہ ابو سفیان نے دربارِ نبویؐ میں دست بستہ حاضر ہو کر صلح کی درخواست کی لیکن نبی اکرمﷺ نے صلح نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل وحئ الٰہی کی روشنی میں نبی اکرم ﷺ کی رہنمائی اور قیادت میں اختیار کیا گیا۔مکی دَور میں پوری جدوجہد پر ایک درویشانہ اور مظلومانہ رنگ غالب ہے جبکہ مدنی دور میں اقدامی اور جارحانہ روش دکھائی دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اسلام نہ ہمیشہ امن اور صلح‘صبر اور در گزر کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی ہر حال اور ہر جگہ جنگ و جدال اورجہاد و قتال پر اُبھارتا ہے۔ اسلام میں فی نفسہٖ نہ صلح مطلوب ہے نہ قتال ‘بلکہ یہ دونوں ایک خاص مقصد کے لیے حکمت عملی کے طور پر اختیار کیے جاتے ہیں‘ اور وہ خاص مقصد ہے اظہارِ دین حق‘ اقامت دین‘ قیامِ خلافت ‘ نصب امامت‘ اقامۃ الدولۃ الاسلامیہ‘ حکومت الٰہیہ کا قیام۔ غرض نام اور اندازِ تعبیر مختلف ہیں مگر ان سب سے ایک ہی حقیقت کا اظہار مطلوب ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلویm نے اِس آیت کو سیرت النبیﷺ کا عمود قرار دیا ہے ‘یعنی یہی وہ نقطہ ہے جس کے گرد پوری تیئیس سالہ جدوجہد گردش کر رہی ہے۔ ارشادِ الٰہی ہے:
(ہُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ بِالْہُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَہٗ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّہٖ) (التوبۃ:۳۳‘ الفتح:۲۸‘ الصف:۹)
’’وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ (کتابِ ہدایت )اور دین حق دے کر تا کہ غالب کر دے اُسے تمام نظام ہائے حیات پر‘‘ ۔
اس آیت مبارکہ میں نبی اکرمﷺ کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے۔ اس نقطہ کو سمجھ لینے کے بعد سیرت کے ہر دو مراحل میں کوئی تضاد اور کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ یعنی جب بھی جو طریقۂ کار غلبۂ دین کے لیے زیادہ مناسب تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبیؐ میں وہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ جب تک مکہ میں رہے مسلمانوں کے پاس اِس قدر قوت نہ تھی کہ کفر کی حکمرانی کو جڑ سے اُکھاڑ پھینکتے اور اُس کی جگہ خدا کی حکمرانی قائم کرتے۔ اِس لیے اقدام نہ کیا بلکہ مسلسل تن دہی کے ساتھ قوت کی فراہمی میں کوشاں رہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں قوت سے مراد صرف عددی قوت نہیں بلکہ ایسی عددی قوت کی فراہمی مطلوب ہے جو ایمانِ حقیقی سے وافر حصہ رکھتے ہوں اور عمل صالح پر کاربند ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مطلوبہ قوت فراہم ہوگئی تورسول اللہﷺ نے باطل کے خلاف اقدام کیا اور بھر پور کیا ۔بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا۔ دراصل یہ نقطہ حکمت دین سے متعلق ہے اور حکمت کی ایک تعریف یوں بھی کی گئی ہے: ’’وضع الشئ فی محلہ‘‘۔ یعنی ہر چیز کو اُس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائے ۔ آمین!
کیا اب مکی منہج ( مرحلۂ دعوت) منسوخ ہے؟
جیسا کہ واضح کیا گیا ‘منہج نبوی ؐکے دو مراحل ہیں جن میں حالات کی رعایت سے مقدم و مؤخر کی نسبت ہے۔ اب مسئلہ یہ در پیش ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض خاص ذہنی پس منظر رکھنے والے افراد جو انقلابِ اسلامی کے طریقہ کار جیسے اہم موضوع پر سنجیدہ علمی و عقلی غور و فکر کے لیے سرے سے تیار ہی نہیں اور مسلمانوں کی موجودہ صورتِ حال پر اس قدر انفعالی کیفیت کا شکار ہیں کہ بغیر کسی استدلال کے نری جذباتیت برتتے ہیں‘ اور جو منہج اُنہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ اصلاً تو کوئی لائحہ عمل ہے ہی نہیں اِلاّیہ کہ اپنے غم و غصہ کا اظہار ہو یا کچھ انتقامی جذبات کی تسکین ہو‘ سر دست ہم اُن کے اِس دعویٰ بلادلیل کا جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا جہاد و قتال کی آیات کے نزول سے دعوت و تبلیغ کا منہج منسوخ ہو گیا ہے؟ وہ آیات جو مکی دَور میں ہاتھوں کو باندھے رکھنے اور برائی کا جواب اچھائی سے دینے ‘ مظالم پر صبر کرنے اور ظلم و جبر کے جواب میں مسلسل دعوت و تنظیم کو مزید بڑھانے کا مطالبہ کرتی ہیں ‘منسوخ ہو چکی ہیں اُن آیات سے جو مدنی دَور میں اذِن قتال اور پھر حکم قتال سے متعلق نازل کی گئیں؟ ہمیں اِس بات کا جائزہ لینا ہے کہ یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟
ہمارے اِن نیک نیت مگر جذبات سے مغلوب بھائیوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ خالص علمی بحث کو چٹکیوں میں اُڑا رہے ہیں جسے اہل علم نے علوم القرآن کی کتب میں خاص اہتمام کے ساتھ ناسخ و منسوخ کے عنوان کے تحت درج کیا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اس ہوائی دعوے کی زد قرآن حکیم کی بیشتر محکم آیات پر پڑتی ہے جس کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ہمیں مخاطب ہی نہیں کرتا۔ یہ قرآن حکیم جو ابدالآباد کے لیے اور بنی نوع انسا ن کے ہر مسئلہ کے لیے اپنے اندر رہنمائی سموئے ہوئے ہے ہم اُسے اپنے جذبات اور جوش و خروش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اتنا محدود کر دیں کہ اُسے غلبۂ دین کی جدوجہد کے صرف ایک دَور کے ساتھ خاص کر دیں‘یہ قرآن پرظلم اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے!
اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے متعلق اہل علم کیا فرماتے ہیں ۔
سب سے پہلے علامہ بدر الدین الزرکشیؒ کی ’البرہان فی علوم القرآن ‘کو لیتے ہیں جس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ موقف علماءِ سوء نے نائن الیون کے بعد مسلمانوں کو مغرب کی غلامی میں دینے کے لیے اختیار کیا ہے (کیونکہ علامہ کا تعلق ساتویں صدی ہجری سے ہے)۔ علامہؒ لکھتے ہیں:
فیما یقع فیہ النسخ: الجمہور علی أنہ لا یقع النسخ إلا فی الأمر والنہی وزاد بعضھم الأخبار وأطلق و قید ھا آخرون بالتی یراد بہا الأمرو النہی (۱)
’’ نسخ کہاں واقع ہوتا ہے؟ جمہور اہل علم کی رائے میں نسخ صرف امر و نہی میں واقع ہوتا ہے اور بعض نے اس پر اخبار (واقعہ کا تذکرہ) کا اضافہ کیا ہے ۔کچھ نے مطلق اخبار کہا ہے اور کچھ نے صرف اُن اخبار پر نسخ کا وقوع مانا ہے جن میں امر و نہی وارد ہوتے ہیں‘‘۔
ملا حظہ ہو کہ جن آیات کے نسخ کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اصلاً تو شریعت سے متعلق نہیں بلکہ منہاج سے متعلق ہیں جس کے متعلق اوپر جمہور کا مسلک درج کیا گیا کہ اِس میں نسخ واقع ہی نہیں ہوتا۔ علامہ کی درج ذیل عبارت پر غور کیا جانا چاہیے جس میں انہوں نے براہِ راست ہمارے پیشِ نظر موضوع سے بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
الثالث ما أمربہ لسبب ثم یزول السبب‘ کالأمر حین الضعف والقلۃ بالصبرو بالمغفرۃ للذین یرجون لقاء اللہ و نحوہ من عدم إیجاب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر والجہاد و نحوھا‘ ثم نسخہ إیجاب ذلک وھذا لیس بنسخ فی الحقیقۃ وإنما ھو نَسٌ‘ کما قال تعالیٰ : ’’أونُنْسِہَا‘‘ فالْمُنسَأ ھو الأمر بالقتال‘ إلی أن یقوی المسلون ‘ و فی حال الضعف یکون الحکم وجوب الصبر علی الأذی(۲)
’’تیسرا یہ کہ جو حکم دیا جائے کسی سبب کی وجہ سے ‘پھر وہ سبب نہ رہے ‘جیسا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کفار کے ظلم پر صبر کرنے اور در گزر کرنے کا ‘اُن مسلمانوں کو جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح(مکی دور میں) امربالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد کے واجب نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا وجوبِ جہاد سے اور یہ درحقیقت نسخ نہیں بلکہ یہ بھلا دینا ہے( بایں معنی کہ وقتی طور پر اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا) جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اَوْنُنْسِہَا۔ تو وقتی طور جو بھلا دیا گیا وہ حکم قتال تھا یہاں تک کہ مسلمان قوت حاصل کر لیں ‘اور ضعف کی حالت میں واجب ہے کہ تکلیف پر صبر کیا جائے‘‘۔
یہ مشاہدہ ہے کہ نسخ کے دعوے دار اکثر ائمہ سلف کی اُن تفسیری آراء سے دلیل پکڑتے ہیں جو آیاتِ قتال کے ذیل میں ان جلیل القدر ہستیوں نے ظاہر فرمائی ہیں۔ اس کے صحیح محل اور مدعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض تابعین نے نُنْسِھَا کی تفسیر نؤخرھا (یعنی مؤخر کرتے ہیں) سے کی ہے۔( ابنِ کثیر ‘جلد اوّل‘ سورۃ البقرۃ‘آیت ۱۰۶)جیسا کہ امام ابن جریر طبری سورۃ الحج کی آیت ۳۹ (اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّھُمْ ظُلِمُوْا) (اجازت دی گئی اُن لوگوں کو جن سے قتال کیا جاتا ہے (قتال کرنے کی) بسبب اس کے کہ اُن پر ظلم ہوا)کے تحت لکھتے ہیں:
وقال ابن زید کانوا قد أمروا بالصفح عن المشرکین‘ فأسلم رجال ذو ومنعۃ فقالوا یا رسول اللہ لو أذن اللہ لنا لأ نتصرنا من ھؤلاء الکلاب‘ فنزلت ھذہ الآیۃ ثم نسخ ذلک بالجہاد(۳)
’’ ہمیں مشرکین سے عدم تعارض کا حکم دیا گیا تھا‘ مگر پھر مقابلہ کی طاقت رکھنے والے لوگ بھی اسلام لے آئے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسولﷺ !اگر اللہ ہمیں اجازت دیتا تو ہم ان کتوں سے خوب بدلہ لیتے ۔تواِس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے عدم تعارض کے حکم کو منسوخ کر دیا‘‘۔
امام سیوطیؒ نے جہاد و قتال سے متعلق اُن تمام آیات کو جنہیں بطورِ ناسخ پیش کیا جاتا ہے‘ اپنی کتاب ’الاتقان فی علوم القرآن‘ میں نانسخ و منسوخ کی بحث کے تحت جمع کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے اس کتاب سے رجوع کیا جائے۔
یہ اور اس جیسے دیگر مقامات جو کتب تفسیر میں پائے جاتے ہیں ‘سے متعلق اس وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہاں نسخ کے معنی وہ نہیں جو نسخ حقیقی کے ہیں‘ یعنی أن رفع الحکم بدلیل شرعی ولا یجوز امتثالہ أبدًا (دلیل شرعی کی بنیاد پر کسی حکم کا ختم ہو جانا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا) بلکہ حکم کے فی الحال معطل اور مؤخر ہونے کے ہیں۔ اورا سی رائے کو امام جلال الدین سیوطیؒ نے اختیار کیا ہے۔
اس بارے میں علامہ زرکشیؒ کا قولِ فیصل درج ذیل ہے :
وبھذا التحقیق تبین ضعفُ ما لھج بہ کثیر من المفسرین فی الآیات الامرۃ بالتخفیف إنھا منسوخۃ بآیۃ السیف‘ ولیست کذلک بل ھی من المنسأ بمعنی أن کل أمر ورد یجب امتثالہ فی وقت ما لعلّۃ توجب ذلک الحکم‘ ثم ینتقل بانتقال تلک العلّۃ الی آخر‘ ولیس بنسخ إنما النسخ الازالۃ حتی لا یجوز امتثالہ ابدًا وإلی ھذا أشار الشافعی فی ’’الرسالۃ‘‘ إلی النہی عن ادّخار لحوم الأضاحی من أجل الرأفۃ‘ ثم ورد الإذن فیہ فلم یجعلہ منسوخا بل من باب زوال الحکم لزوال علّتہ وھو سبحانہ و تعالیٰ حکیم أنزل علی نبیہ ﷺ حین ضعفہ ما یلیق بتلک الحال رأفۃ ورحمۃ‘ إذ لو وجب لاؤرث حرجا و مشقۃ‘ فلما أعز اللّٰہ الاسلام وأظہرہ ونصرہ أنزل علیہ من الخطاب ما یکافی تلک الحالۃ من مطالبۃ الکفار بالاسلام أو بأداء الجزیۃ ان کانو أھل کتاب أو الاسلام أو القتل إن لم یکونوا أھل کتاب ویعود ھذان الحکمان‘ اعنی المسالمۃ عند الضعف والمسایفۃ عند القوۃ بعود سببھما‘ ولیس حکم المسایفۃ ناسخًا لحکم المسالمۃ بل کلٌّ منہما یجب امتثالہ فی وقتہٖ (۴)
’’اور اِس تحقیق سے وہ ضعف واضح ہو تا ہے جو بہت سے مفسرین کو لا حق ہوا اُن آیات کے بارے میں جن میں بہت زیادہ تخفیف کا حکم ہے(یعنی صبر و استقامت اور عفو ودرگزر کا حکم ہے) کہ یہ تمام آیات منسوخ ہیں آیۃ السیف سے۔جب کہ معاملہ ایسا نہیں ہے ‘بلکہ اوّل الذکر آیات منساء (مؤخرکردہ) کی قبیل سے ہیں‘ اس معنی میں کہ جو بھی حکم وارد ہوا ہے اُس کا پورا کرنا واجب ہے ایک خاص وقت میں جو علت ہے اُس حکم کے وجوب کی۔ پھر وجوب منتقل ہو جاتا ہے دوسرے حکم کی طرف علت کے منتقل ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ ہر گز نسخ نہیں ہے‘ بلکہ نسخ تو وہ ہے جس پر ہمیشہ کے لیے عمل کرنا جائز نہ رہا ہو۔ امام شافعیؒ نے اپنی کتاب ’’الرسالہ‘‘ میں اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ: حدیث میں جو قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا (۵) تو وہ بسبب رأفت ہے ۔پھر ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی تو یہ اجازت پہلے حکم کی ناسخ نہیں ہے‘ بلکہ اِس میں بھی وہی حکمت کار فرما ہے کہ علت کے زائل ہونے سے حکم بھی زائل ہو گیا۔اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ حکمت والے ہیں اِس لیے اپنے نبیﷺ پر حالت ضعف میں وہ احکام نازل فرمائے جو اُس حال کے مطابق تھے‘ نرمی برتتے ہوئے رحمت کے ساتھ۔ اگر شروع ہی سے قتال کے احکام واجب کر دیے جاتے تو اِس سے شدید حرج اور مشقت لازم آتی۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو عزت ‘نصرت اور غلبہ سے سرفراز فرمایا تو آپﷺ پر وہ احکام نازل فرمائے جو اِس حال کے مطابق تھے۔ جیسے کفار سے اسلام کا مطالبہ (جزیرہ نمائے عرب کے کفار مراد ہیں) ورنہ اُن کا قتل کر دیا جانا ‘یا اگر اہل کتاب ہیں تو جزیہ کا مطالبہ۔یہ دونوں حکم واپس آ سکتے ہیں سبب کے لوٹنے سے ۔ یعنی امن(عدم جنگ) کا اختیار کرنا کمزوری کے وقت اور جنگ و قتال کا اختیار کرنا قوت و طاقت کے وقت ۔ اور ’حکم المسایفۃ‘ (قتال و جنگ کا حکم) ’حکم المسالمۃ‘ (امن و عدم جنگ کے حکم)کے لیے ناسخ نہیں‘ بلکہ اُن میں سے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ اوقات میں عمل ہو گا‘‘۔
پس ثابت ہوا کہ نسخ کا دعویٰ مکی منہج یعنی منہج دعوت کے لیے کسی طور پر بھی ثابت نہیں۔ احوالِ واقعہ یعنی معروضی حالات کی نسبت سے معاملہ مقدم اور مؤخر کا ہے نہ کہ ناسخ و منسوخ کا ۔ نہ منہج دعوت منسوخ ہے اور نہ منہج جہاد (جیسا کہ اس کے برعکس اکثر متجددین کا زعمِ باطل ہے)۔ منہج جہاد و قتال بھی اپنی پوری شان و شوکت‘ جاہ و جلال ‘وقار وطمطراق کے ساتھ موجود ہے اور منہج جہاد و قتال کو ساقط یا منسوخ قرار دینے والا اور اِس پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے والا مغلوب ذہنیت کا حامل‘ حقائق کا منکر ‘ اسلام کی تکمیلی شان سے ناواقف اور مارِآستین ہے۔ مگر یہاں محل گفتگو یہ ہے کہ کون سا منہج کن حالات میں زیادہ مناسب للمطلوب ‘ مؤثر ‘ راجح‘ مقدم اور مقاصد شریعت کا زیادہ محافظ اور غلبہ و اقامت دین کے لیے مبنی برہدف ہے۔ واللّٰہ المُستعان!
ایک اشکال اور اُس کا حل
زیر نظر مضمون کا یہ بنیادی مقدمہ ہے کہ آج مسلمانوں میں کام کرنے والی تحریکاتِ اسلامیہ کے لیے رہنمائی کا اہم ترین ذریعہ نبی اکرم ﷺ کے مکی دور کا منہج ہے۔ ہمارے نزدیک یہی وہ بنیادی مقدمہ ہے جس کو تسلیم کر لینے سے اسلامی تحریکات جو غلبہ واقامت دین کے لیے مصروف کار ہیں ‘صحیح راہ پر گامزن رہیں گی اور منزل بہ منزل نفاذِ اسلام اور نظامِ خلافت سے قریب تر ہوتی چلی جائیں گی اور پھر اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اُس کے تحت اور امامِ شرعی کی اقتدا میں کفار کے خلاف قتال کو منظم کرنے کا مرحلہ بھی آئے گا (اِن شاء اللہ)۔
اس استدلال پر ایک اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ اگر آج جدوجہد کے لیے مکی دور کو نظیر ٹھہرایا جائے تو پھر وہ حلت و حرمت کی تفصیلات جو شریعت میں تدریجی مراحل سے گزرنے کے بعد اپنی حتمی شکل کو پہنچ چکی ہیں‘ درہم برہم ہو جائیں گی‘ شراب و سؤر کی حلت و حرمت کا سوال اُٹھ کھڑا ہو گا ۔ اِس اشکال کو ایک معترض کی زبانی سنیے! ہم عبارت نقل کیے دیتے ہیں:
’’جب جہاد کے حتمی احکامات نازل کیے جا چکے تو اب کسی کو یہ حق نہیں کہ موجودہ دور کو مکی دور کے مثل قرار دے کر جہاد کو معطل کر دے‘ کیونکہ اِس طرح تو آج شراب و سود کی عدم حرمت کا سوال بھی کھڑا ہو جائے گا کہ مکی دور میں یہ بھی حرام نہ تھے۔ جبکہ ہمارے سامنے اللہ کا یہ حکم موجود ہے :(اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلاَمَ دِیْنًا) (المائدۃ:۳) ’’آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں رضا مند ہو گیا‘‘۔
الغرض ہمارے لیے شریعت کے حتمی احکام ہی حجت ہیں۔
یہ اعتراض خلط مبحث کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی نظیر یا مثال کا سوفیصد انطباق نہیں ہوتا‘ بلکہ کسی نسبت سے اُس کا اطلاق ہوتا ہے اور کسی پہلو سے نہیں بھی ہوتا ۔ اُسوۂ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ عقل عام کی بات ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔
ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:
(لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۃً وَّمِنْہَاجًا) (المائدۃ:۴۸)
’’تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت دی اور ایک منہاج‘‘۔
اِس آیت میں دو غور طلب الفاظ وارد ہوئے ہیں‘ ایک شریعت اور دوسرا منہاج۔ آئیے دیکھتے ہیں لغت میں اس کے معنی کیا ہیں ‘ اِس آیت کی ماثور تفسیر کیا ہے اور سلف نے اِ س سے کیا مراد لی ہے۔ اِس نقطے کی تفہیم سے اِن شاء اللہ محولہ بالا اشکال کا جواب بھی حاصل ہو جائے گا۔
لفظ’’ الشِّرعۃ ‘‘ کے بارے میں علامہ آلوسی البغدادی ؒ لکھتے ہیں:
’الشِّرعۃ‘ بکسر الشین‘ و قرأ یحیی بن ثاب بفتحھا ’الشَّریعۃ‘ وھی فی الأصل الطریق الطاھر الذی یوصل منہ إلی الماء والمراد بھا الدین‘ واستعمالھا فیہ لکونہ سبب موصلا إلی ما ھو سبب للحیاۃ الأبدیۃ کما أن الماء سبب للحیاۃ الفانیۃ أو لأنہ طریق إلی العمل الذی یطھر العامل عن الأوساخ المعنویۃ کما أن الشریعۃ طریق إلی الماء الذی یطھر مستعملہ عن الأوساخ الحسیۃ(۶)
’’الشِّرعۃ شین کی زیرکے ساتھ ہے اور یحییٰ بن ثاب کی قرا ء ت میں زبر کے ساتھ ہے۔ اور اِس کے اصلی معنی ہیں ایسا صاف طاہر راستہ جو پانی تک پہنچتا ہو اور اِس سے مراد دین ہے‘ اور اِس کا آیت میں استعمال ان معنی میں کیا گیا ہے کہ دین سبب ہے حیاتِ ابدی کا جیسا کہ پانی سبب ہے حیاتِ فانی کا ۔یا یہ کہ یہ وہ راستہ ہے جو عامل کو ایسے عمل کی طرف لے کر جاتا ہے جو اُسے معنوی آلائشوں سے پاک کرتاہے‘ جیسا کہ شریعت اُس راستہ کو کہتے ہیں جو ایسے پانی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اُس کا استعمال کرنے والا حسی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے‘‘۔
اب لفظ ’’منہاج‘‘ کے متعلق تفصیلات ملا حظہ ہوں:
’’مِنْہَاجًا‘‘ اسم آلہ مفردہے اور اس کا مطلب ہے کھلا ہوا راستہ‘ کشادہ راستہ‘ روش۔ نہج‘ منہج اور منہاج تینوں ہم معنی ہیں۔ نَہْجٌ باب فَتَحَ سے مصدر ہے اور مراد ہے راستہ کا کشادہ اور صاف ہونا اور اُس پر چلنا‘کپڑے کا پرانا ہونا ‘ کپڑے کو پرانا کرنا۔ اِس معنی میں باب سَمِعَ اور کَرُمَ سے بھی مستعمل ہے۔ انہاجٌ ’’لازم‘‘ بن کر بھی آتا ہے اور ’’متعدی‘‘ بھی ۔ یعنی اس کا مطلب کشادہ راستہ ہونا بھی ہے اور راستہ کشادہ کرنابھی ۔(۷)
ملاحظہ کیجیے کہ ائمہ سلف نے اس آیت کی تفسیر میں اِن الفاظ کے شرعی معنی کیا بیان کیے ہیں۔ امام ابن جریر طبری ؒ نے اس آیت کے ذیل میں کئی روایات جمع کی ہیں جن کے طرق مختلف ہیں مگر معنی میں اشتراک ہے۔ ہم یہاں ایک روایت نقل کرتے ہیں:
حدثنا ابن بشار ‘ قال ثنا عبدالرحمن بن مہدی ‘ قال ثنا مسعر عن ابی اسحاق عن التمیحی ‘ عن ابن عباس: لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۃً وَّمِنْہَاجًا قَالَ سُنَّۃً وَ سَبِیْلًا(۸)
’’۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آیت(لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۃً وَّمِنْہَاجًا) سے مراد سنت (یعنی شرعی طریقہ و حکم) اور سبیل (یعنی اس شرعی حکم اور طریقے پر چلنے کا رستہ) ہے‘‘۔
معلوم ہوا کہ شریعت اور منہاج میں فرق ہے ۔یہ دونوں الفاظ الگ الگ مفاہیم کی ادائیگی کے لیے وارد ہوئے ہیں مگر یہ فرق ایک ہی حقیقت یعنی دین کے دو پہلوؤں کے اظہار کے اعتبار سے ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اِ س آیت کے ذیل میں کافی و شافی کلام فرمایا ہے جس سے مدعا واضح ہوجاتا ہے ۔ وہ کہتے ہیں:
و (الحقیقۃ) حقیقۃ الدین‘ دین ربّ العالمین ھی ما اتفق علیھا أنبیاء والمرسلون‘ وإن کان لکل منھم شرعۃ ومنہاج فالشرعۃ ھی الشریعۃ قال اللہ تعالیٰ: (ثُمَّ جَعَلْنٰکَ عَلٰی شَرِیْعَۃٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْھَا وَلَا تَتَّبِعْ اَھْوَآءَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ o اِنَّہُمْ لَنْ یُّغْنُوْا عَنْکَ مِنَ اللّٰہِ شَیْئا ط وَاِنَّ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضُھُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍج وَاللّٰہُ وَلِیُّ الْمُتَّقِیْنَ) (الجاثیۃ) ۔ (والمنہاج) ھو الطریق قال تعالیٰ: (وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَی الطَّرِیْقَۃِ لَاَسْقَیْنَاہُمْ مَّآءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَھُمْ فِیْہِ ط وَمَنْ یُّعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّہٖ یَسْلُکْہُ عَذَابًا صَعَدًا) (الجِنّ) فالشرعۃ بمنزلۃ الشریعۃ والمنہاج ھو الطریق الذین سلک فیہ والغایۃ المقصود ہی حقیقۃ الدین وھی عبادۃ اللّٰہ وحدہ لا شریک لہ وھی حقیقۃ دین الاسلام (۹)
’’حقیقۃ سے مراد حقیقتِ دین ہے‘ یعنی اللہ ر بّ العالمین کا دین۔ یہ وہ دین ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں fکے درمیان متفق چلا آ رہا ہے باوجود اِس کے کہ اُن سب کے لیے شریعت اور منہاج علیحدہ علیحدہ تھے۔ پس ’ الشرعۃ‘سے مرادشریعت ہے‘ جیسا کہ فرمانِ باری ہے:’’ پھر ہم نے رکھا آپ کوایک شریعت پر اس کام میں تو اسی کی پیروی کیجیے‘ اور ہرگز نادان لوگوں کی خواہشات کی پیرو ی مت کیجیے ۔ وہ کام نہ آئیں گے آپ کے اللہ کے سامنے کچھ بھی‘ اور بے شک ظالم تو ایک دوسرے کے دوست ہیں ‘اور اللہ دوست رکھتا ہے متقین کو‘‘۔اور’منہاج ‘ سے مراد ہے طریقہ کار‘ راستہ۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے :’’اگر لوگ سیدھے طریقہ پر رہتے تو ہم اُنہیں پلاتے پانی بھر کر‘ تا کہ ہم اُن کو اس کے ذریعہ چانچیں ۔اور جو کوئی منہ موڑے اپنے ربّ کی یاد سے تو وہ اُس کو چلا دیتا ہے چڑھتے ہوئے عذاب میں‘‘۔پس شرعۃسے مراد شریعت ہے اور منہاج سے مراد وہ طریقہ کار ہے جس پر چل کر غایت مقصود حاصل کیا جاتا ہے جو کہ حقیقت دین ہے اور یہ حقیقت اصلاً اللہ وحدہ لاشریک کی بندگی کا نام ہے‘‘۔
اِسی طرح کئی اور مقامات پر امام ابن تیمیہؒ نے واضح کیا ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقہ کار الگ ہے۔ اور یہ تمام انبیاء ؑ کے لیے مختلف رہی ہیں‘ مگر دین کی حقیقت جو کہ عبادتِ ربّ واحد ہے ‘وہ تمام انبیاء اور رُسل ؑ کے ما بین متفق رہی ہے۔ شریعت بحث کرتی ہے حلا ل و حرام سے ‘جائز و ناجائز سے ‘اشیاءِ استعمال کے مستحب و مکروہ ہونے سے ‘جبکہ منہاج اُس طریقہ کار‘ اُس حکمت عملی‘ اُس راستہ اور منہج کو کہتے ہیں جس پر کار بند ہوکراللہ کی بندگی‘اظہارِ دین اور اعلا ءِ کلمۃ اللہ کی جدوجہد کی جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر بات واضح ہوجاتی ہے کہ آج اقامت دین کے لیے رسول اللہ ﷺ کے دیے گئے دو مراحل منہج میں سے کسی کے اختیار کرنے سے شریعت کے معطل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک شریعت مکمل ہو چکی ‘جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
(اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا)
یعنی آج منہج نبویؐ کے مرحلۂ دعوت پر عمل کرنے کے باوجود شریعت کے حلال و حرام پر کوئی فرق واقع نہیں ہو گا۔ آج ہمارے لیے شر یعت کے وہی احکام حجت ہیں جو تدریجی مراحل سے گزرنے کے بعد اپنی تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ آج شریعت کے بہت سے احکام پر ہمارے ہاں عمل نہیں۔ خاص طور پر شریعت اسلامی کا وہ حصہ جو ریاست سے متعلق ہے ۔ جیسے نفاذِ حدود ‘ نظامِ صلاۃ ‘ نظامِ زکوٰۃ ‘ کفار کے خلاف شرعی قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا قیام‘ امر بالمعروف ونہی عن المنکر بالید ‘ حرمتِ سود ‘ کفارسے جزیہ کامطالبہ وغیرہ ۔کوئی مانے یا نہ مانے تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنے ربّ کے ان احکام پر اجتماعی طور پر عمل کرنے سے عاجز ہیں۔ اس کا تدارک صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ہم اس فرمانِ حقیقت بیان کی روشنی میں اسلامی ریاست کے قیام کی جدو جہد کریں۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایاتھاکہ: لَن یصلح آخر ھذہ الأمۃ الا بما صلح بہ أولھا، اور منہج انقلابِ نبویؐ کی رو سے جدوجہد کی ترتیب میں مکی دَور مقدم ہے اور اسی کا ثمر ریاست مدینہ کے نام سے معروف ہے۔
نصوص سے غلط استدلال
یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ آج اصل اعتبار قرآن مجید سے استنباطِ احکام کے وقت عمومِ لفظی کا ہوگا نہ کہ سبب خصوصی کا ۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۔مگر یہ قاعدہ احکامِ شریعت سے متعلق ہے نہ کہ استخراجِ منہج سے۔ استخراجِ منہج میں تواصل اعتبار ترتیب نزولی کا ہے اور یہ بات اتنی سامنے کی ہے کہ اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔
آج ایک خاص طرح کے لٹریچر میں جہاں بہت سے اصولی اور علمی خلط مبحث پائے جاتے ہیں، اُ ن میں سب سے خطرناک اور کثرت سے پائی جانے والی خامی نصوص کا بے موقع انطباق ہے۔ یعنی آیا تِ قرآنی ‘ احادیث نبویؐ ‘ فتاویٰ و اقوالِ سلف کو سیاق و سباق ‘ ظروف و احوال سے کاٹ کر یکسر بے محل پیش کیا جاتا ہے‘جو کہ نتیجہ ہے اُس حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت‘ انتقامی جذبات اور عالم کفر کی طرف سے ڈھائے جانے والے مسلسل ظلم و جبر کا‘ جس کے نتیجہ میں ہمارے یہ بھائی موجودہ پستی کی کیفیت سے باہر آنے اور غلبۂ اسلام کے لیے منہج و طریقہ کار پر سنجیدہ غور و فکر کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور زبانِ حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں : ع
مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے
میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے!
اور :
نصیحتم چہ کنم ناصحاچہ میدانی
کہ من نہ معتقد مردِ عافیت جوییم
مگر یہ الزام درست نہیں ‘کیونکہ ہم مفاہمت یا عافیت جوئی کی تعلیم نہیں دے رہے ‘بلکہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی نبوی حکمتِ عملی کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔
مفہوم اور مرادِ متکلم کے اخذ کرنے میں سیاق و سباق اور احوال و ظروف کی حد درجہ اہمیت ہے ۔ اس بات کا اندازہ ہم ایک سادہ سی مثال سے لگا سکتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے ’’ پانی لاؤ‘‘۔ اب اگر وہ شخص یہ جملہ کھانے کی میز پر ادا کرے گا تو آپ اُس کو پانی کا ایک گلاس لا دیں گے۔ اگر یہی جملہ غسل خانے سے کوئی پکار کر کہے تو آپ بالٹی بھر پانی کا اہتمام کر یں گے اور اگر یہی جملہ کوئی وضو خانے میں کہے تو آپ اُسے پانی کا ایک ظرف فراہم کر دیں گے۔غور طلب بات یہ ہے کہ جملہ ایک ہی ہے مگر محل و مقام کے بدلنے سے تعمیل حکم میں کتنا فرق واقع ہوتا ہے! اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیاق و سباق اور احوال و ظروف اور مزاج و لہجے کا متکلم کی مراد کو سمجھنے میں کتنا حصہ ہے۔
سیاق و سباق سے کاٹ کر نصوص کو پیش کرنے کے حوالے سے ہم ایک روایت کا تذکرہ کرتے ہیں ۔ عصر حاضر کے جہادی لٹریچر میں آپ کو بخاری و مسلم سے مروی یہ حدیث نبویؐ جابجا ملے گی:
((اَنَّ الْجَنَّۃَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّیُوْفِ)) (صحیح مسلم)
’’ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے‘‘۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک روایت کا جزو ہے نہ کہ مکمل حدیث۔ اب آپ مکمل حدیث نبویؐ کا مطالعہ فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ سیاق و سباق کے ساتھ اِس حدیث کا کیا مفہوم ہے اور سیاق و سباق سے کاٹنے کے بعد اس کے معنی میں کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ ارشادِ نبویؐ ہے:
((یَا اَیُّھَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْاَلُوا اللّٰہَ الْعَافِیَۃَ‘ فَاِذَا لَقِیْتُمُوْھُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّۃَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّیُوْفِ)) (۱۰)
’’ اے لوگو! دشمن سے لڑنے کی آرزو نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو۔ پس جب لڑنے کی نوبت آہی جائے تو ڈٹ جاؤ(بھاگو نہیں) اور یہ جان رکھو کہ بہشت تلواروں کے سائے تلے ہے۔(یعنی شہید ہوتے ہی داخل جنت ہو گے)‘‘۔
اِس طرح کے لٹریچرکا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ اِس میں ائمہ‘سلف کے فتاویٰ کو اُن کے پورے استدلال سے کاٹ کر الگ اور بے محل پیش کیا جاتا ہے‘ بغیر اِس پر غور کیے کہ صاحبِ فتویٰ نے یہ فتویٰ کن حالات میں اور کن امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیا تھا۔اِس لیے ضروری ہے کہ فتوے کی شرعی حیثیت اور اُن عوامل کو دیکھ لیا جائے جن کا ایک مفتی فتویٰ دیتے وقت لحاظ رکھتا ہے۔ اِس سے یہ بات صاف واضح ہوجاتی ہے کہ اسلاف میں سے کسی کے فتویٰ سے منہج کے لیے دلیل پکڑنا درست نہیں‘ کیونکہ منہج کا تعلق اپنے زمانے کے خاص حالات سے ہوتاہے۔ منہج کے تعین میں فیصلہ کن عامل کی حیثیت وقت کے عرف و عادت اور مصالح مرسلہ کو حاصل ہے۔اسی لیے اہل علم کے ہاں مشہور ہے کہ: من لم یعرف اھل زمانہ فھو جاھلٌ۔کہ ’’جو شخص اہل زمانہ کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے‘‘ ۔اور عالم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ: ان یکون بصیرًا بزمانہ کہ وہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو۔علامہ شامی کا شعر ہے:
والعرف فی الشرع لہ اعتبار
لذا علیہ الحکم قد یدار
’’عرف کا شریعت میں اعتبار ہے ‘اس لیے کہ اِس پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے‘‘۔
دکتور عبدالکریم زیدان (استاذ الفقہ المقارن ‘ جامعہ صنعاء) نے اپنی شاہکار تألیف ’’اصول الدعوۃ‘‘ میں باب نظام الافتاء کے تحت اِس موضوع پر عمدہ بحث کی ہے‘ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فتویٰ کا خاص تعلق احوال‘ امکنۃ‘ ازمنۃ‘ ظروف اور مستفتی کے حالات سے ہوتا ہے اور یہ فتویٰ اِن امور کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے ۔یعنی والفتویٰ قد تتغیر بتغیر المکان والزمان(۱۱) قواعد فقہ کی کتب میں یہ قاعدہ کلیہ مسلّمہ حیثیت کا حامل ہے کہ:
والحکم یدورمع العلۃ وجودًا و عدمًا۔ ’’حکم کا مدار وجوداً اور عدماً علت پر رہے گا‘‘۔
علامہ ابن عابدین الشامی ’’عقود رسم المفتٰی‘‘ میں رقم طراز ہیں:
إن کثیرًا من الاحکام التی نص علیہ المجتھد صاحب المذہب بناء علی ما کان فی عرضہ وزمانہ قد تغیرت بتغیر الازمان بسبب فساد اھل الزمان أو عموم الضرورۃ کما قد مناہ من افتاء المتأخرین (۱۲)
’’یقیناًبہت سے احکام جن کی تصریح صاحب مذہب مجتہد نے اپنے عرف اور اپنے زمانہ کے احوال پر بنیاد رکھتے ہوئے کی تھی وہ زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں اور یہ تبدیلی یا تو لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا عمومی ضرورت کا لحاظ پیش نظر ہوتا ہے ‘جیسا کہ ہم متأخرین کے فتاویٰ کے ذیل میں پہلے بیان کر چکے ہیں ‘‘۔
ان تصریحات سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خاص حالات میں دیے گئے فتاویٰ سے منہج کے لیے آج استدلال کرنا درست نہیں ‘وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلم ممالک میں ہر جگہ ایک ہی منہج کو اختیار کرنا بھی ضروری نہیں۔ جیسا کہ بعض ممالک براہِ راست کافر اورغیر ملکی افواج سے اپنی حریت و آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں فوری ضرورت کے پیش نظر مرحلۂ دعوت کا التزام کارگر نہیں ہے۔
آخر میں ہم مولانا سید ابو الا علیٰ مودودیؒ کی وہ نصیحت نقل کر تے ہیں جو آپ نے بزبانِ عربی‘ عرب ممالک کے نوجوانوں کو حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں ۱۳۸۲ھ میں فرمائی تھی۔ اس نصیحت کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھنے کی ضرورت ہے ۔جب مولانا مرحوم نے یہ تقریر فرمائی تھی تو اُس وقت سے زیادہ شاید آج مسلمانوں کو اس رہنمائی کی ضرورت ہے ۔ہم اِس تقریر کا ایک جزو نقل کیے دیتے ہیں:
’’اِس سلسلے میں اسلامی تحریک کے کارکنوں کو میری آخری نصیحت یہ ہے کہ انہیں خفیہ تحریکیں چلانے اور اسلحہ کے ذریعہ سے انقلاب بر پا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے(۱۳) ۔ یہ بھی دراصل بے صبری اور جلد بازی کی ایک صورت ہے اور نتائج کے اعتبار سے دوسری صورتوں کی بہ نسبت زیادہ خراب ہے۔ ایک صحیح انقلاب ہمیشہ عوامی تحریک ہی کے ذریعہ بر پا ہوتا ہے۔ کھلے بندوں عام دعوت پھیلائیے‘ بڑے پیمانے پر اذہان اور افکار کی اصلاح کیجیے‘ لوگوں کے خیالات بدلیے‘ اخلاق کے ہتھیاروں سے دلوں کو مسخر کیجیے۔ اِس طرح بتدریج جو انقلاب بر پا ہو گا وہ ایسا پائیدار اور مستحکم ہو گا جسے مخالف طاقتوں کے ہوائی طوفان محو نہ کر سکیں گے۔ جلد بازی سے کام لے کر مصنوعی طریقوں سے اگر کوئی انقلاب رونما ہو بھی جائے تو جس راستے سے وہ آئے گا اسی راستے سے وہ مٹایا بھی جاسکے گا۔‘‘ (۱۴)
حوالہ جات
۱) البرھان فی علوم القرآن ۲/۳۳۔
۲) البرھان فی علوم القرآن ۲/۴۲۔
۳) الطبری ۱۸/۳۲۴۔
۴) البرھان فی علوم القرآن ۲/ ۴۲‘ ۴۳۔
۵) حدیث میںآتا ہے کہ رسول اللہﷺ نے دیہاتی غرباء کی وجہ سے یہ حکم دیا تھا کہ : ((اِدَّخِرُوْا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِیَ))’’تین دن کا گوشت ذخیرہ کر لو اور باقی گوشت صدقہ کر دو‘‘۔ اس کے بعد لوگوں نے آکر عرض کیا اے اللہ کے رسولﷺ ! لوگوں نے تو اپنی قربانی سے مشکیزے بنا لیے ہیں اور اُن میں چربی کی چکناہٹ مل رہے ہیں۔ تو آپؐ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس پر لوگوں نے آپﷺ کا گزشتہ حکم بیان کیا تو آپؐ نے فرمایا :((اِنَّمَا نَھَیْتُکُمْ مِنْ اَجَلِ الرَّاْفَۃِ فَکُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا))’’میں نے تو صرف اُن آنے والے غربا ء کی سہولت کی وجہ سے تمہیں منع کیا تھا۔ اب تم کھاؤ ‘ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو‘‘۔ مسلم ۱۹۸۱۔ واحمد ۶/۵۱۔ وابوداوٗد ۲/۲۸۔ والنسائی ۸/۲۳۵۔
۶) تفسیر روح المعانی للعلامۃ شہاب الدین آلوسی البغدادی ص۱۵۳ج ۶ آیت ۴۸ سورۃ المائدۃ۔
۷) تاج العروس‘ لغات القرآن جلد پنجم ص ۴۶۴۔
۸) رقم : ۹۴۶۷ص ۳۳۶المجلد الرابع جامع البیان عن تاویل آی القرآن للام ابن جریر طبریؒ ۔
۹) مجموع الفتاوی للشیخ الاسلام ابن تیمیہ ؒ ۱۱/۲۱۸‘۲۱۹۔
۱۰) صحیح البخاری‘ کتاب الجھاد والسیر‘ باب کان النبیﷺ اذا لم یقاتل اول النھار آخر القتال۔ وصحیح مسلم‘ کتاب الجھاد والسیر‘ باب کراھۃ تمنی لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاءِ۔
۱۱) اصول الدعوۃ لدکتور عبدالکریم زیدان‘ ص۱۲۹‘۱۸۰بیروت۔
۱۲) عقود رسم المفتی لابن عابدین الشامی ص۳۸۔
۱۳) ظاہر ہے یہ ہدایت مولانا نے آج کے خاص حالات کے حوالے سے فرمائی ہے ورنہ اسلام میں مسلح کارروائی چند شرائط کے ساتھ کوئی ممنوع شے نہیں۔ (مضمون نگار)
۱۴) ماخود از تفہیمات حصہ سوم سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ ’’ دُنیائے اسلام میں اسلامی تحریکات کے لیے طریق کار۔‘‘
تشدد، محاذآرائی، علیحدگی اور غلبہ
پروفیسر میاں انعام الرحمن
تقسیم ہند سے تقریباً نوے برس قبل ۱۸۵۷ میں لڑی جانے والی جنگ آزادی کا اصل مقصد، اسلام کا نفاذ نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف، اپنے علاقے سے غیر ملکیوں کو کھدیڑنا تھا۔ اس لیے اس جنگ میں متحدہ ہند کی تمام قوموں نے بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل مقدور بھر حصہ لیا تھا۔ شاید اسی لیے اس واقعہ کی بابت یہ بحث تو ہوتی رہی کہ یہ جنگ ہے یا غدر۔ لیکن، یہ جہاد ہے یا نہیں؟ اس زاویے سے کوئی سنجیدہ بحث ہمارے علم کی حد تک کبھی نہیں چھڑی۔ جن لوگوں نے اسے ’جنگِ آزادی‘ قرار دیا اور جنہوں نے اسے ’غدر‘ گردانا، دونوں ہی اپنے اپنے موقف کے تاریخی اثرات سے پوری طرح آگاہ نہ تھے۔جنگِ آزادی کو غدر گرداننے والوں نے مسلمانوں کو انگریز حاکموں کے ظلم و استبداد سے بچانے کی اپنے تئیں کوشش کی۔ لیکن اس کوشش کے دوران میں انہوں نے (شاید نادانستہ طور پر) متحدہ ہند کی دیگر اقوام سے مسلمانوں کے فکری و معاشرتی فاصلے بہت بڑھا دیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو دلہن کی دو آنکھوں کے مانند سمجھنے والے سر سید احمد خان مرحوم بھی ’بھینگی دلہن‘ پر فریفتہ ہو گئے۔ پھر تاریخ نے عجیب منظر دیکھا کہ متحدہ ہند کی وہ اقوام جو جنگِ آزادی میں ایک دوسرے کی پشتیبان تھیں، حالتِ امن میں دوبدو کھڑی ہو گئیں۔ مسلمان چونکہ سابق حکمران تھے، اس لیے اس عمل کے زیادہ ذمہ دار تھے۔ سرسید مرحوم جیسے بالغ نظر قائد کا متحدہ ہند کے مسلمانوں کے الگ تشخص پر بے جا زور اور اصرار اس امر کا آئینہ دار تھا کہ مسلم قائدین ’پر امن بقائے باہمی‘ جیسے آفاقی اصول کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اگر تسلیم کرتے ہیں تو ان قائدین میں اتنی صلاحیت موجود نہیں کہ اس اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسلم تشخص اور مسلم شناخت کا تحفظ یقینی بنا سکیں۔ افسوس ناک بات یہ ہے کہ سرسید احمد خان کی وفات کے بعد جناح مرحوم اور اقبال رحمتہ اللہ علیہ بھی بہت با صلاحیت ثابت نہیں ہو سکے۔ ان دونوں عظیم قائدین کی تان بھی علیحدگی پسندی پر آ کے ٹوٹی۔
مذہب کی بنیاد پر قومی علیحدگی پسندی کا تاریخی واقعہ متحدہ ہند کے بجائے دنیا کے کسی چھوٹے سے علاقے میں رونما ہوتا تو اور بات تھی۔ لیکن متحدہ ہند ایک بر عظیم تھا جس کا اعتراف سرسید مرحوم نے بھی کیا تھا اور اسی اعتراف کی بنیاد پر انہوں نے متحدہ ہند میں ایک قوم کے بجائے زیادہ قوموں کے وجود پر اصرار کیا تھا۔ یوں سمجھئے کہ تقسیم سے قبل کا بر عظیم، ایک مِنی ورلڈ تھا، مِنی گلوب تھا۔ اس عالمِ صغیر (mini world) میں عالم کبیر(all the world over) کے مانند کئی نسلیں، کئی زبانیں، کئی ثقافتیں، کئی مذاہب موجود تھے۔ جس طرح عالمِ کبیر (عام پوری دنیا) میں کوئی ایک قوم، نسل مذہب زبان ثقافت وغیرہ کی بنیاد پر ایسی مہم جوئی کی جرات نہیں کرسکتی، جس کے نتیجے میں اسے یا باقی پوری دنیا کو (مثال کے طور پر) مریخ میں آباد ہونا پڑے، اسی طرح عالمِ صغیر (متحدہ ہند) میں کسی قوم کا اپنے تشخص پر اس انداز اور اس درجے کا اصرار، جس کے نتیجے میں اسے یا باقی مقامی اقوام کو سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑے، اس قوم میں پر امن بقائے باہمی جیسی زریں اقدار کی بے وقعتی کی، غمازی کرتا ہے۔ پاکستان کی خالق جماعت آل انڈیا مسلم لیگ نے مذہب کے نام پر متحدہ ہند کی دیگر اقوام سے جس سطح کی علیحدگی پسندی کو (تشخص و شناخت کے نارمل درجے سے بہت بڑھ کر) رواج دیا، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ’اسلام‘ کا ایسا ایڈیشن سامنے آیا جس میں کسی بھی ’دوسرے‘ کو برداشت کرنے کا حوصلہ باقی نہ رہا۔ خیال رہے اگر اسلام کے بجائے کوئی اور مذہب ہوتا اور اس کے قائدین مسلم لیگی طرزِ عمل جیسا طرزِ عمل اختیار کرتے تو اس مذہب کی بنیادی ساخت بھی تشدد، عدمِ برداشت اور علیحدگی پسندی سے اسی طرح متاثر ہوتی، جس طرح اسلام کی بنیادی ساخت متاثر ہوئی۔
متحدہ ہند کی مسلم لیگ کا علیحدگی پسندانہ رویہ، اس لیے قابلِ گرفت ہو جاتا ہے کہ اس عالمِ صغیر میں صرف مسلم قوم کے مفادات ہی غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ بہت سی دیگر اقوام بھی اپنے معلق مفادات کے تحفظ کے لیے میدانِ عمل میں برسرپیکار تھیں۔ لیکن ان اقوام کی لیڈرشپ نے اپنے قومی مفادات کو اس انداز سے پیش نہیں کیا کہ عالمِ صغیر(متحدہ ہند) کے اجتماعی نظم اور اجتماعی مفاد سے شدید ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی۔ اندریں صورت نہ صرف مسلم لیگی قائدین کی یہ صلاحیت مشکوک ہو جاتی ہے کہ وہ مسلم شناخت کے اثبات کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام کے مفادات سے ہم آہنگ طرزِ عمل کا مظاہرہ کر سکتے، بلکہ دین اسلام کی بابت بھی قدرتی طور پر سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں ایسی تعلیمات موجود ہیں جو اس کے پیروکاروں کو ’دوسروں‘ کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے سے روکتی ہیں۔ اس نوعیت کے سوالات کا جنم لینا اس لیے لازمی تھا، کیونکہ لیگی قیادت کے ذریعے سے مسلم قوم اپنے مذہب ہی کی بنیاد پر عالمِ صغیر (متحدہ ہند)کے اجتماعی نظم اور اجتماعی مفاد کو چیلنج کر رہی تھی۔ گردشِ ایام کے ساتھ دین اسلام کی بابت اس نوع کے سوالات بڑھتے گئے اور دیگر اقوام تحفظات کا شکار ہوتی گئیں۔
اقبالؒ کو اپنی ’خودی‘ کی علیحدگی پسندانہ ہیبت کا احساس ہو کہ نہ ہو، لیکن جناح مرحوم کو کسی نہ کسی درجے میں اس امر کا ادراک ضرور تھا کہ عالمِ صغیر (متحدہ ہند) کی وحدت و عظمت پر جس طرح مذہبیت کے تیشے سے وار کیے گئے ہیں، اس کے اثرات وار کرنے والوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ (کہ مریخ پر زندگی، زمینی زندگی کی طرح بہت قدرتی نہیں ہو سکتی)۔ اس مذہبیت کو اعتدال میں لانے کے لیے یا دوسروں لفظوں میں مریخ کی زندگی کو زمینی زندگی سے ممکن حد تک مماثل کرنے کے لیے، محمد علی جناح مرحوم نے اس سیکولر رویے کو رواج دینے کی کوشش کی، جس کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے متحدہ ہند کے اجتماعی نظم اور اجتماعی مفاد کو بری طرح روند ڈالا تھا۔ جناح مرحوم پاکستان کو انتہائی چھوٹے پیمانے پر عالمِ کبیر (عام پوری دنیا)کے مانند بنانا چاہتے تھے جس میں ہر مذہب ہر نسل ہر زبان ہر ثقافت کے لوگ اپنے اپنے تشخص و شناخت کے اثبات کے ساتھ اجتماعی نظم و مفاد سے آہنگ زندگی بسر کر سکیں، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ متحدہ ہند کے اجتماعی نظم و مفاد کے منافی جس مذہبیت کو جناح مرحوم نے پروان چڑھایا تھا، وہ درحقیقت مذہبیت سے زیادہ ایک انتہائی منفی رویہ تھا۔ خیال رہے کہ انسانی گروہوں میں یہ رویہ کبھی مذہب کی صورت میں کبھی نسل کی صورت میں کبھی زبان کی صورت میں اور کبھی ثقافت یا علاقائی شناخت کی صورت میں جلوہ گر ہوسکتا ہے۔ متحدہ ہند میں محمد علی جناح مرحوم اس منفی رویے کی مذہبی جہت سے ہائی جیک ہوئے، اور اسی منفی رویے کی لسانی، علاقائی اور ثقافتی جہت نے ۱۹۷۱ میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں ( متحدہ پاکستان کے اجتماعی نظم و مفاد کے منافی) وہی عمل دہرایا جو ۱۹۴۷ میں متحدہ ہند کے اجتماعی نظم و مفاد کے منافی خود جناح مرحوم سے سرزد ہوا تھا۔
بیسویں صدی کے دوسرے ربع کی متحدہ ہند کی سیاست پر نگاہ دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی اقوام کے درمیان رہتے ہوئے تعاونِ باہمی اختیار کرنا اور اپنے گروہی مفادات ممکن حد تک حاصل کرتے رہنا، آسان کھیل نہ تھا۔ متحدہ ہند کی سیاست، فولادی اعصاب کا تقاضا کر رہی تھی۔ انہی دنوں آل انڈیا مسلم لیگ نے انڈین نیشنل کانگرس کی سیاست سے زِچ ہو کر ردِ عمل میں تحریکِ پاکستان کی داغ بیل ڈالی۔ مسلم لیگ نے علیحدگی کے غیر سیاسی طرزِ عمل سے غالب آنے کی ٹھان لی۔ اس لیے تحریکِ پاکستان اپنی اصل میں، (غیر سیاسی اور) سمجھوتہ نہ کر سکنے والی ذہنیت کی تحریک تھی۔ اس ذہنیت نے عدم برداشت کے ایسے رویے کی آبیاری کی، جس کے نزدیک کسی بھی’دوسرے‘ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ چونکہ یہ ایک مکمل منفی رویہ تھا جسے قبولیتِ عامہ نہ مل سکتی تھی، اس لیے اس میں ’غلبے‘ کو نمایاں کیا گیا تاکہ مسلم قوم کی معتدبہ اکثریت غلبے کی خواہش سے مجبور ہوکر اس تحریک سے منسلک ہو جائے۔ اس طرح مذہبی جواز پر مبنی دو انتہا پسندانہ رویے ’علیحدگی اور غلبہ‘ متحدہ ہند کے مسلمانوں کی رگ رگ میں سما گئے۔ یہ بہت سامنے کی بات ہے کہ پیچیدہ سیاسی عمل سے جب کچھ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو غلبے کی نفسیات سے دمڑی ہتھیانے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے۔
مذکورہ نکات کی مجموعی معنویت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عالمِ صغیر (متحدہ ہند) میں دین اسلام کے نام پر دیگر اقوام کے ساتھ مل جل کر نہ رہنے کے رویے نے مسلمانوں میں تشدد، علیحدگی اور غلبے کی نفسیات کو جنم دیا۔ المیہ یہ ہے کہ اس نوع کی اقدار، دین اسلام کی بھی پہچان بن گئیں۔ قیامِ پاکستان کے بعد کی نسل نے اسی نوعیت کے نفسیاتی ماحول میں آنکھ کھولی۔ جس نسل کے آباو اجداد اور فکری قائدین نے ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی میں، متحدہ ہند کی سیاست کی حد تک، تشدد محاذآرائی علیحدگی اور غلبے سے اجتناب کیا تھا اور عالمِ صغیر میں پرامن بقائے باہمی کے اصول کو نہ صرف نظری طور پر تسلیم کیا تھا بلکہ قومی زندگی کے عملی احوال کا حصہ بھی بنایا ہوا تھا، وہ نسل تخلیقِ پاکستان کے بعد فکری طور پر یرغمال ہو گئی۔ آج پاکستان میں جن لوگوں پر تشدد، دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے، ان کے فکری و نسلی رشتے درحقیقت ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے ان حریت پسندوں سے جا ملتے ہیں جنہوں نے (ہند کی داخلی سیاست میں)تشدد کے بجائے صبر اختیار کیا، علیحدگی پسندانہ رجحانات کے بجائے ہجرت کی راہ اپنائی اور غلبے کی خواہش کو حدِ اعتدال میں رکھتے ہوئے نفسیاتی مسئلہ نہ بننے دیا۔
بحث کے اس مقام پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا دین اسلام میں علیحدگی پسندی کی کوئی گنجائش موجود ہے؟یا علیحدگی پسندی کی تطہیر کرتے ہوئے صرف ’ہجرت‘ کی گنجائش باقی رکھی گئی ہے؟ کیا عصری تناظر میں ہجرت کا مفہوم اتنا وسیع ہو سکتا ہے کہ اس کی سیاست کاری (politicization) کے ذریعے علیحدگی پسندی کو اس میں سمو دیا جائے؟ بنظرِ غائر معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام، علیحدگی پسندانہ جذبات اور ہجرت کے جواز میں واضح فرق قائم کرتا ہے۔ اگر کوئی قوم یا کسی قوم کے افراد اپنے آپ کو بہت مصائب کا شکار دیکھیں تو بجائے تشدد اور محاذ آرائی کے، انہیں ہجرت کی راہ اختیار کرنی چاہیے(ہجرتِ حبشہ اور ہجرتِ مدینہ کی مثال لے لیجیے)۔ متحدہ ہند کی مسلم قوم کے جس گروہ نے مصائب کی سنگینی بھانپتے ہوئے علیحدگی پسندی کی راہ اپنائی(خیال رہے کہ بعضوں کے نزدیک مسائل اتنے گھمبیر نہیں تھے)، اگر وہ دین اسلام کے تصورِ ہجرت کا گہرائی سے جائزہ لیتا تو آج مسلمان اور اسلام پوری دنیا میں اس طرح بدنام نہ ہوتے، علیحدگی پسند اور انتہا پسند نہ کہلاتے، بلکہ بیرونِ ہند علاقہ جات (مثلاًآسٹریلیا و کینیڈا و امریکہ) میں (ہجرتِ حبشہ و ہجرتِ مدینہ سے مماثل) اپنے مفاہمتی و تخلیقی طرزِ عمل سے نئی دنیا کی تشکیل میں بھر پور کردار ادا کرتے۔
ہمیں یہ تلخ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جو تحریکیں اسلام کے نام پر جاری ہیں، وہ اپنی اصل میں قومی تحریکیں ہیں۔ جس طرح متحدہ ہند میں قوم پرستوں کے مقابلے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلم قوم پرستی کو استعمال کیا(اس استعمال کا ثبوت پاکستان کی پوری تاریخ ہے) اور لیگ نے کامیابی بھی حاصل کر لی، اسی طرح مختلف مسلم تحریکیں اسلام کو’آلہ کار‘ کے طور پر استعمال کرر ہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم قوم پرستی، مسلمانوں کے اجتماعی ملی وجود کے ساتھ منسلک ہے جس کا اظہار ماضی میں خلافت کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس وقت مسلم ملی وجود کے منظم اظہار کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں، او آئی سی ایامِ طفولیت میں ہے۔ منظم ملی وجود (جو مختلف قومیتوں کو ان کی شناخت کے اثبات کے ساتھ اپنے اندر سمو لیتا ہے)کے بعد ہی غالباً اسلام کے تصورِ جہاد کا عملی مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جہاد کے بجائے خلافت جیسے ادارے کی بحالی کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان گنت قوم پرست شناختوں کے علاوہ امت کا ملی وجود بھی دنیا کے سامنے آ سکے۔ کسی قسم کے ملی وجود کے بغیر ’جہاد‘ کرنا درحقیقت قومی مفادات کے لیے اسلام کو استعمال کرنا ہے جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔
یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کو غدر قرار دینے والے اور متحدہ ہند کی سیاست میں علیحدگی پسندانہ رجحانات لانے والے شناخت بھی کر لیے جائیں تو اس سے آج کے ماحول پر کیا کسی قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یا یہ محض ذہنی عیاشی اور خلط مبحث ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بحث کی عصری معنویت اس لحاظ سے قابلِ غور ہے کہ پاکستان میں تشدد اور علیحدگی کی موجودہ لہروں کی جڑیں انہی تاریخی واقعات میں پیوست ہیں۔ آج کا پاکستان ۱۸۵۷ کی جنگِ آزادی کی حالت میں ہے۔ جس طرح ۱۸۵۷ میں نسلی مذہبی لسانی اور علاقائی تعصبات سے بالاتر ہو کر غیر ملکیوں کو اپنے علاقے سے کھدیڑنے کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، اسی طرح تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج بھی غیر ملکیوں کو اپنے علاقے سے بھگانے کی اشد ضرورت ہے۔ زحمت میں رحمت کے مصداق، غیر ملکیوں کی مداخلت کی وجہ سے، کم از کم پاکستان کی حدود کے اندر اندر مختلف شناختوں کی حامل قومتیوں کو ’پر امن بقائے باہمی‘ کے اصول کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر کسی قومیت کو سر سید احمد خان مرحوم کے مانند بھینگی دلہن پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی جناح و اقبال کی طرح کسی کانگرسی رویے (آج کے ماحول میں فوج، بیوروکریسی، عدلیہ، اسٹیبلیشمنٹ یا کسی سیاسی و مذہبی اور علاقائی جماعت وغیرہ)سے زِچ ہو کر ردِ عمل میں (غیر سیاسی ہوتے ہوئے) ایسی علیحدگی پسندی میں پناہ ڈھونڈنی چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کا اجتماعی نظم و مفاد تتر بتر ہو جائے(جیسا کہ ایک مرتبہ ۱۹۷۱ میں ہو چکا ہے )۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ مثبت سمت میں گامزن ہونے کے لیے نام نہاد نظریاتی شناخت کے حامل آج کے پاکستان کی مذہبیت کو سیاسی پالیسیوں کی حد تک ایک مخصوص مفہوم میں سیکولر ازم کے سامنے جھکنا ہو گا کہ اسی سے نہ صرف فرقہ وارانہ کشیدگی اور مذہبی منافرت میں خاطر خواہ حد تک کمی آئے گی بلکہ نسلی، لسانی اور علاقائی تعصبات بھی حدِ اعتدال میں رہ پائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی اس جہت پر توجہ مرکوز کرنی ہو گی جو اپنی اپروچ میں سیکولر ازم سے زیادہ سیکولر ہے، جو مسلم (مذہبی)شناخت کے اثبات کے ساتھ ساتھ دیگر شناختوں (غیر مسلم یا غیر مذہبی یعنی لسانی نسلی وغیرہ) کی اہمیت کو کھلے بندوں تسلیم کرتی ہے۔ یہ کام بہت مشکل نہیں کہ ہم اس سے قبل ۱۸۵۷ میں اسلام کے اس مفاہمتی و انقلابی پہلو کا عملی مظاہرہ کر چکے ہیں۔
خیال رہے کہ قومی زندگی میں اسلام کے مفاہمتی و انقلابی پہلو کے در آنے سے ’جہاد‘ پر بھی نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو گی۔ اگر ایک طرف نظریہ جہاد کا عملی مظاہرہ کیا جائے اور دوسری طرف اسلام کے سیکولر ازم سے زیادہ سیکولر پہلو کو اپنانے کی بھی کوشش کی جائے تو یہ اجتماع ضدین ہو گا جو محال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ملی اور قومی زندگی کے دائروں کو کماحقہ نہیں سمجھ پاتے تو نادانستگی میں قومی مفادات کے لیے اسلام کو استعمال کرنے کی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بدنامی اسلام کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سوویت یونین کے خلاف کیے جانے والے ’جہاد‘ کو لے لیجیے اور ٹھنڈے دل سے ذرا غور کیجیے کہ کیا یہ صحیح معنوں میں اسلام کے تصورِ جہاد کے عین مطابق تھا؟ کیا ہمارے ملی وجود کو کوئی خطرہ لاحق تھا؟کیا ملی وجود کے ذریعے یہ جہاد کیا گیا؟ اگر یہ جہاد تھا تو اس کے دوران میں اور اس کے خاتمے کے بعد مختلف قوموں نے مسلم ہوتے ہوئے بھی اس جہاد میں قومی مفادات کو ترجیح کیوں دی؟ کیا سوویت یونین کے خلاف کی گئی اس عالمی جنگ میں جہاد کی پوری شرائط موجود تھیں؟ جس طرح مختلف عالمی طاقتوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے ہمیں مالی و فوجی امداد بہم پہنچائی اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد انہی طاقتوں نے اسی نام نہاد جہاد کے استحصال کے ذریعے پاکستان اور دین اسلام کے خلاف پوری دنیا میں مہم چلائی، اور پاکستان تو پاکستان، دین اسلام تک کو دہشت گرد مذہب قرار دیا، اس سے ہمیں کم از کم اب تو یہ سبق ضرور سیکھ لینا چاہیے کہ قومی زندگی کے ہنگامی معاملات میں اگر دین اسلام کو اسی طرح استعمال کیا جاتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب غیر مسلم قومیں تو اسلام کے نام سے بدکیں گی ہی، خود ہماری نئی نسل بھی دینی حریت کے معاملے میں دیوالیہ ہو جائے گی۔
حافظ صفوان محمد کے جواب میں
طلحہ احمد ثاقب
محب گرامی حافظ محمد صفوان نے ’’سماجی، ثقافتی اور سیاسی دباؤ اور دین کی غلط تعبیریں‘‘ کے زیر عنوان مضمون میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا فریضہ بہت خوب صورتی سے سرانجام دیا ہے۔ اچانک چلتے چلتے وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو چھوڑ کر ہامز لامز بن گئے ہیں۔ انھوں نے ایک ماسٹر صاحب کا تذکرہ فرمایا ہے جو ان کو لے کر ایک مذہبی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور لے گئے۔ پھر ان کی گزارش یا مطالبے پر انھیں بادشاہی مسجد لے گئے۔ انھوں نے مزار اقبال پر جانا چاہا تو اقبال کے بارے میں بڑی عجیب وغریب باتیں ان کے کانوں میں انڈیلیں۔ بقول ان کے ماسٹر صاحب ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے جو قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہ تھی۔ آگے چل کر انھوں نے چند اور باتیں کہی ہیں جو ترتیب وار درج ذیل ہیں:
۱۔ پاکستان اگر مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی کچھ جماعتوں کے مزاج اور توقعات کے مطابق نہیں بنا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
۲۔ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ سیاسی اختلاف رکھنے والا کلمہ گو کیسے کافر ہو سکتا ہے؟
۳۔ سید القوم سرسید احمد خان، مولانا حالی، سر آغا خان، ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح وغیرہ ہماری قومی وملی تاریخ کے ڈیڑھ ہزار سالہ سفر میں آنے والی تاب ناک کہکشاؤں میں سے چند بڑ ے نام ہیں۔
۴۔ یہ وہ مردان راہ رواں ہیں جو ستاروں کے لیے نشانات راہ ہیں اور جن کی مختلف جہتوں میں کی گئی سنجیدہ اور پیہم کوششوں سے مسلمانان ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ان دور اندیش اور دردمند لوگوں نے ان شاطر انگریزوں کی بچھائی ہوئی بساط پر انھیں ہرا کر ہم درماندہ مسلمانوں کے لیے آزادی چھینی۔
۵۔ جن لوگوں نے جس جس دور میں اقبال شکنی، جناح شکنی یا سرسید شکنی کی ..... وہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ ان کو آج جانتا کون ہے؟ یہ بڑے لوگ ..... کارواں ران ہوتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، منزل پا لیتا ہے۔ جو ان کے منہ کو آتا ہے، وہ کارواں سے ٹوٹ جاتا ہے۔
حافظ صفوان محمد چوہان کے ماسٹر صاحب نے اقبال کے بارے میں ناروا باتیں کہی تھیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہ ہونے والے جمعیۃ علماء ہند کے علما ہوں یا مجلس احرار اسلام کے کارکنان وراہ نما، کبھی کسی بزرگ نے علامہ اقبال کے بارے میں کوئی ناروا بات نہیں لکھی۔ اگر ایسی کوئی بات جناب چوہان کے علم میں ہو تو وہ ہمیں بھی بتا دیں۔ ہاں علامہ سے اختلاف کا حق ہر عہد کے سوچنے والے دماغ کو حاصل رہا ہے۔ اگر کسی بزرگ نے علامہ سے دلائل کی بنیاد پر اختلاف کیا تو یہ ان کا حق تھا۔ علامہ اقبال تو کیا، ان سے کہیں بڑے لوگوں سے اختلاف کیا گیا۔ حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام بخاری اور ان کے مقام ومرتبہ کے لوگوں سے اختلاف کیا گیا اور ہر کسی نے اس حق اختلاف کو تسلیم کیا۔ حافظ صفوان محمد چوہان یاد رکھیں، فیصلہ شخصیات کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی بنیا دپر ہوتا ہے۔
اب ہم حافظ صاحب کے دعاوی کو نمبر وار دیکھتے ہیں اور ان پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔
ان کا یہ دعویٰ ہمیں تسلیم ہیں کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کلمہ گو کو کافر ٹھہرائے۔ اب یہ حافظ چوہان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ سے یہ ثابت کریں کہ کس گروہ نے سیاسی اختلاف کی بنیاد پر دوسرے گروہ کو کافر ٹھہرایا۔ جمعیۃ علماء ہند کے علما نے یا مسلم لیگ کے کارکنوں نے؟ کس نے مخالف پر قاتلانہ حملے کیے او رکس نے مخالفین کے منہ پر تھوکنا اور ان کی پگڑیوں کو پاؤں تلے روندنا، روا سمجھا؟ آپ براہ کرم جمعیۃ علماء ہند کے لٹریچر سے صرف ایک جملہ نکال کر دکھا دیں کہ فلاں بزرگ نے فلاں وقت پر سیاسی اختلاف کی بنیاد پر فلاں کوکافر ٹھہرایا۔ اگر آپ مولانا مظہر علی اظہر کے ایک شعر کا حوالہ دیں تو یہ ناکافی ہوگا۔ مولانا موصوف کے اس شعر کی احرار کے لوگوں میں پذیرائی نہیں ہوئی تھی۔ علماء کرام کے خلاف لیگی کارکنوں نے جو سب وشتم کیا، اس کی تفصیل کے لیے آپ اس دور کے اخبارات دیکھ لیجیے۔ علما نے جو رویہ اپنایا، اس کے متعلق ایک مسلم لیگی غلام کبریا کی کتاب ’’آزادی سے پہلے مسلمانوں کا ذہنی رویہ‘‘ اور عبید الرحمن خان کی ’’مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا‘‘ پڑھ لیجیے۔
حافظ چوہان نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان اگر مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی کچھ جماعتوں کے مزاج اور توقعات کے مطابق نہیں بنا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں! آپ یقیناًکچھ بھی نہیں کر سکتے کہ خود کردہ را علاجے نیست۔ ویسے یہ بات آپ کے کان میں کہنے کی ہے کہ مذہب کے نام پر سیاست مسلم لیگ نے کی تھی۔ جمعیۃ علماء ہند تو کانگریس کے ساتھ تھی اور سیکولر سیاست کی قائل تھی۔ ہاں دین کے تحفظ کے معاملے میں وہ پوری طرح کمٹڈ جماعت تھی۔ مسلم لیگ کے اکابرین سیکولر زندگی گزارتے تھے اور خیر سے مذہب کے نام پر سیاست فرما رہے تھے۔ بعض مسلم لیگی اکابر نے یہ تاثر دیا تھا کہ پاکستان میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت راشدہ کا احیا ہوگا۔ یہاں آئے تو ملک غلام محمد، سر ظفر اللہ اور جوگندر ناتھ منڈل براجمان نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں عدل ہوگا، مگر یہاں قتل وغارت گری کا سلسلہ رہ رہ کر پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ۱۹۷۱ء کے مشرقی پاکستان میں جو قتل عام ہوا، اس میں پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہ ہونے والے لوگ کسی طرح بھی شریک نہیں تھے۔ اس میں دونوں طرف سے پاکستان بنانے والے لوگ تھے۔ ۱۹۷۱ء کے مشرقی پاکستان میں قتل عام، بلوچستان، سرحد اور کراچی میں ہونے والے فسادات، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ واقعی علما کے مزاج اور توقعات کے خلاف ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
تیسر ے نمبرپر موصوف کا دعویٰ انھی کے لفظوں میں پیش کیا گیا ہے۔ میں یہ جملے لکھ کر کانپ اٹھا ہوں۔ میں سمجھا تھا کہ موصوف نے ڈیڑھ سو سال لکھا ہوگا، مگر یہاں تو ڈیڑھ ہزار سال ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک بھی شامل ہے۔ اس ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ امت میں آقاے دو جہاں اور آپ کے برگزیدہ وخدا رسیدہ صحابہ کرام تاریخ کے ڈیڑھ ہزار سال کے سفر میں تاب ناک کہکشائیں ہیں تو کیا میں اسی صف میں ان لوگوں کو شامل کرنے کو برداشت کر لوں جن کے نام حافظ چوہان کے قلم نے اگل دیے ہیں؟ اس حرکت کو اہل علم خفیف الحرکتی کہیں یا کچھ اور، میرا خیال ہے حافظ چوہان ڈیڑھ ہزار سال پر شرمندہ ہو کر تائب ہو جائیں تو بہتر ہے اور ڈیڑھ سو سال پر اکتفا کر لیں تو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ ناموں کی اس فہرست میں سر آغا خان بھی شامل ہیں۔ سر آغا خاں نزاری فرقے کے آغا خانی گروپ کے پیشوا تھے۔ آپ کا عہدہ امام حاضر کا تھا۔ ان کے فرقے میں سجدہ حاضر امام کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اس فرقے کے علم الکلام میں اللہ تعالیٰ حاضر امام میں معاذ اللہ حلول کر چکا ہے۔ وہاں کلمہ طیبہ یا روزہ نماز کا تذکرہ بھی نہیں۔ سرآغا خان نے کہا تھا کہ وہ شراب پیتے ہیں تو ان کے اندر نور اترتا ہے۔ موصوف ریس کے بھی شیدا تھے۔ اب امت کی تاریخ میں یہی کہکشاں رہ گئی ہے تو امت کے حال پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔
محترم حافظ صفوان محمد چوہان نے امت کو مختصر زمان ومکان میں قید کر دیا ہے۔ ان کا space پاکستان کی حدود کے اندر واقع ہے اور زمان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ڈیڑھ سو سالہ تاریخ کو ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ کا قائم مقام بنا لیا ہے۔ امت اگر پاکستان سے باہر بھی کہیں بستی ہے تو حافظ صفوان خود ہی غور فرمائیں کہ ان برگزیدہ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے نزدیک بھی تاریخ کی کہکشاں ہیں۔ انھیں چھوڑیں، انھیں ہماری قیادت نے write off کر دیا تو ہمیں کیا پڑی کہ ان کی رائے کو ذرا سی بھی اہمیت دیں، اگرچہ ان کی تعداد ہم پاکستان کے مسلمانوں سے کافی زیادہ ہے۔ محترم حافظ صفوان صاحب بنگال کے مسلمانوں کی رائے کو بھی کچھ اہمیت دینا پسند کریں گے؟ وہ پاکستان کے باغی سہی، اسلام کے باغی تو قطعاً نہیں ہیں۔ ان مسلمانوں کی رائے میں حافظ صفوان کی ممدوح ہستیوں کی ہستی کیا ہے اورحیثیت کیا ہے؟
اب ذرا پاکستان میں بھی دیکھ لیں۔ ہم نے ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی کو ٹی وی چینل پر یہ کہتے سنا ہے کہ وہ جی ایم سید اور ولی خان کے نظریہ قومیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ دونوں لوگ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ صوبہ سرحد کے لوگ بھی مسلمان ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی جان لیتے تو اچھا تھا۔ بلوچستان سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی چوہان صاحب تک ضرور پہنچی ہوں گی۔ ذرا امت کا تصور کیجیے اور پھر سوچیے کہ سر آغا خان کو امت کے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ وہ خود ہی بتائیں تو بہتر ہے۔امت کا سواد اعظم انھیں مسلمان مانتا ہے یا نہیں، یہ بھی انھیں معلوم ہوگا۔ ویسے وہ کلمہ گو کی تعریف میں نہیں آتے۔ ان کے زیر اطاعت جماعت خانوں میں نماز کی ابھی تک اجازت نہیں۔ ایک باغی گروہ ’’اسماعیلی نمازی کمیٹی‘‘ عدالت کے دروازے پر کھڑا یہ استدعا کر رہا ہے کہ انھیں جماعت خانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت ہو۔ وہاں ایک خاص کتاب پڑھی اور سنی جاتی ہے اور امام کی تصویر کو سجدہ کیا جاتا ہے۔
چوتھا نکتہ بہت دلچسپ ہے۔انھوں نے سرسید احمد خان، آغا خان او رمولانا حالی پر آزادی خواہی کی تہمت دھری ہے۔ ان اکابر نے ہمیشہ دعاکی تھی کہ سرکار انگلشیہ کا اقبال بلند ہو اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ حافظ چوہان کو یقین نہ آئے تو سرسید کے خطبات موجود ہیں، وہ ایک بار پڑھ لیں۔ اس سے انھیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو قارئین ان کی طول نویسی سے بچ سکیں گے، دوسرے حافظ چوہان زیادہ بے خبر نہیں رہیں گے۔
پانچواں نکتہ بڑا دلچسپ ہے۔ انھوں نے سرسید شکنی، اقبال شکنی اور جناح شکنی کرنے والوں پر بہت تبرا کیا ہے۔ موصوف یہ بھول گئے کہ سرسید شکنی، اقبال شکنی اور جناح شکنی صرف انھی لوگوں نے کی ہے جو ان حضرات کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ سرسید نے ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ مسلمانوں کو سرکار انگریزی کا ہمیشہ وفادار رہنا چاہیے۔ انھوں نے کبھی بھولے سے بھی ایسا جملہ نہ کہا جو سرکار انگریزی کی رضا کے خلاف تھا۔ انھی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے محمد علی جوہر دیوبند جا کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ہم سفر ہوئے اور آزادی کے سفر پر چل دیے۔ اب رہی اقبال شکنی تو ان لوگوں نے کبھی اقبال کو مسترد نہیں کیا، ہاں ان سے علمی اختلاف ضرور کیا۔ رہی جناح شکنی تو اس کا آغاز ۱۴؍ اگست ۱۹۴۷ء کو اس مسلم لیگی قیادت نے کیا جو تقسیم کے نتیجے میں ہندوستان میں رہ گئی اور پاکستان نہ آ سکی۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو اعلیٰ مسلم لیگی قیادت کی یادداشتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جناح شکنی کا دوسرا دوربنگال میں شروع ہوا جب جناح صاحب نے کہا کہ پاکستان میں صرف اور صرف اردو ہی قومی زبان ہوگی۔ اس کا انجام ۱۶؍ دسمبر ۱۹۷۱ء کو ڈھاکا کے پلٹن میدان میں ہوا۔ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہ ہونے والے لوگ نہ پہلے دور میں شامل تھے نہ دوسرے دور میں۔ تیسرا دور سندھ میں ہوا جب کھوڑو نے جناح صاحب کی حکم عدولی کی، یہ دور ابھی جاری ہے۔ بہرحال ان تینوں ادوار میں جناح شکنی کا کام کرنے والے لوگ خود مسلم لیگ سے آئے ہیں، ان میں سے کسی کا تعلق نہ جمعیۃ علماء ہند سے ہے نہ احرار اسلام سے۔ اب جناح شکنی کرنے والے لوگ تاریخ میں کہاں جاتے ہیں؟ تاریخ میں گم ہوتے ہیں یا بنگلہ بندھو بنتے ہیں؟ بنگال کے جنرل عثمانی نے قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگی کارکن اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طالب علم کی حیثیت سے مولانا ابو الکلام آزاد سے جو بدتمیزی روا رکھی تھی، ۱۹۷۱ء میں اس سے زیادہ بدتمیزی جناب جناح کی تصویر سے روا رکھی۔
اب سرسید شکنی، اقبال شکنی اور جناح شکنی کرنے والوں میں محمد علی جوہر اور شیخ مجیب الرحمن کو کون جانتا ہے، یہ تو حافظ صفوان بھی بخوبی جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مخالفین کی فہرست کا تذکرہ اس لیے گول کر دیتے ہیں کہ بات فرقہ واریت میں چلی جائے گی۔ ہاں حافظ صفوان اپنا پاسپورٹ دیکھیں اور سوچیں کہ ان کی قومیت مسلمان کی بجائے پاکستان لکھی ہوئی ہے، یعنی ان کی قوم وطن کی بنیاد پر ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ یہ بات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کہی تھی تو گردن زدنی ٹھہرے تھے۔ اب جن لوگوں نے پاکستان کی قومیت مسلم کے بجائے پاکستانی ٹھہرائی ہے، انھوں نے بھی اقبال شکنی کا مظاہرہ کیا ہے یا حقیقت پسندی کا؟ اب حافظ چوہان اور جے سالک کی قومیت صرف جغرافیے کی بنیاد پر پاکستانی ٹھہری ہے۔ ویسے تو حافظ چوہان کو اپنے غیرمسلم بزرگوں سے کوئی ایسی نفرت نہیں، ورنہ وہ چوہان کیوں کر کہلواتے! ان کے تایا پروفیسر غلام رسول نے اسلام کی خاطر غیر اسلامی نسبتیں تج دی تھیں اور وہ انصاری کہلاتے تھے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حافظ چوہان خود اقبال شکنی کی راہ پر چلے دیے ہیں۔
جناب محمد عمار خان ناصر کی خدمت میں
پروفیسر خالد شبیر احمد
جناب محمد عمار خان ناصر صاحب کے بارے میں، میں کچھ نہیں جانتا نہ ہی ان کے علم وفضل کے خد وخال سے پوری طرح آگاہ ہوں کہ ان کا علم وفضل میں کیا مقام ومرتبہ ہے۔ البتہ ان کے والد محترم کی کئی تقریریں سننے کا اعزاز مجھے حاصل ہے اور میں ان کی علمی عظمت کا بھی قائل ہوں۔ جہاں تک ان کی خاندانی عظمت کا تعلق ہے، اسے تسلیم نہ کرنا بھی کوتاہی وکم نظری کے مترادف خیال کرتا ہوں۔
محمد عمار خان ناصر کے ایک مضمون پر مولانا عبد القیوم حقانی صاحب کا تنقیدی مضمون میری نظر سے گزرا جس میں انھوں نے جناب عمار خان ناصر کی اس تحریر پر گرفت کی ہے جو انھوں نے قادیانیوں کے بارے میں تحریر کی ہے۔ عمار خان ناصر تحریر فرماتے ہیں:
’’اگر کسی معاشرے میں کشف والہام انفرادی دائرے سے اٹھ کر ایک باقاعدہ اداراتی صورت اختیار کر چکے ہوں، ان کی بنیاد پر شخصیات اور جماعتوں کے عند اللہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کیے جاتے ہوں، لوگوں کو ان کی طرف دعوت جاتی اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کو نجات کی بشارت دی جاتی ہو، القا والہام کی بنیاد پر مراقبہ وسلوک کے نظام مرتب کیے جاتے بلکہ سیاسی ومذہبی اختلافات میں بھی حق وباطل کی تفریق کرنا ایک عام چلن ہو، جہاں خواب اور بشارات کسی کے مامور من اللہ ہونے کا ایک مستند ذریعہ سمجھے جاتے ہوں، ایسی فضا میں اگر کوئی شخص ’’شبانی سے کلیمی دو قدم ہے‘‘ کا نعرۂ مستانہ بلند کر دے اور لوگ اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اسے ایک ’’امتی نبی‘‘ مان لیں تو انھیں کس حد تک قصور وار ٹھہرایا جا سکتا ہے اور راہ راست پر لانے کی ہمدردانہ کوشش کی بجائے ان کا معاشرتی مقاطعہ کرنے اور قانونی اقدامات کے ذریعے سے انھیں مسلمانوں سے الگ تھلگ کر دینے کو کس حد تک اخلاق، حکمت اور دعوت دین کے تقاضوں کے مطابق قرار دیا جا سکتا ہے؟‘‘
جناب محمد عمار خان ناصر کی مندرجہ بالا تحریر بظاہر بڑی بھولی بھالی، انتہائی مسکین اور عاجزانہ سی نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے اور غور وفکر سے کام لیا جائے تو انتہائی خطرناک، گمراہ کن اور قابل مذمت بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بے چاری اللہ کی مخلوق ہماری غفلت کی وجہ سے ہم سے کٹ کر الگ ہو گئی، انھیں دعوت حق دے کر ساتھ ملانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور ان کے نزدیک مسلمانوں کا یہ رویہ اخلاقی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ گویا ان کی نگاہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو امتی نبی مان لے تو اس بے چارے کا کیا قصور ہے کہ اسے ملت اسلامیہ سے الگ تھلگ کر دیا جائے؟ ان کی اس معصوم خواہش پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ:
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
قادیانیوں کو دعوت حق دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش پر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی شدت کے ساتھ یہ خواہش تھی کہ کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے جو اسلام قبول کر کے ملت اسلامیہ کا فرد نہ بن جائے، بلکہ آپ کی یہ خواہش اس قدر شدید ہو گئی کہ آپ اس کے بارے میں متفکر رہنے لگے تو علما بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہہ دیا تھا کہ آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس بارے میں آپ متفکر نہ رہا کریں کہ اللہ کو ہی علم ہے کہ کس نے اسلام قبول کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا۔ عمار ناصر کو بھی اسی انداز میں سوچنا چاہیے کہ یہی اسوۂ حسنہ کا تقاضا ہے۔
اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے ہے کہ جن قادیانیوں نے اسلام قبول کرنا تھا، انھوں نے مشکل حالات میں بھی اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر لینے کے بعد رد قادیانیت کا دینی فریضہ زندگی بھر سرانجام دیتے رہے اور جنھوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا، وہ آج تک قادیانی ہیں۔ عمار ناصر صاحب کو قادیانیوں پر اتنا ترس کیوں آ رہا ہے؟اس ترس اور اس خواہش کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ عبد الرحمن مصری کی مثال سے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ عمر بھر مرزا بشیر الدین محمود کی خرمستیوں کے خلاف علم بغاوت تو بلند کرتا رہا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور قادیانی مرا، جبکہ اس کے بیٹے حافظ بشیر احمد نے مرزائیت ترک کی، دہریت کی دہلیز تک پہنچا اور پھر اسلام قبول کر کے عمر بھر دینی خدمات سرانجام دیتا رہا۔ عمار ناصر صاحب کو اس بات کا کیوں علم نہیں کہ جسے دین اسلام قبول نہیں کرنا، ا س کے ساتھ خواہ آپ کتنا ہی مخلصانہ اور مہربانہ رویہ اختیار کرلیں، نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔
پھر یہ بات بھی محل نظر ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو اپنے سے الگ کیا ہے۔ ہم نے نہیں، انھوں نے اپنے آپ کو ہم سے علیحدہ کیا ہے جس کا ہم پر الزام سرے سے درست ہی نہیں ہے۔ تو پھر عمار ناصر صاحب کا یہ واویلا کس حقیقت کی نشان دہی کرتا ہے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ ان کی اپنی سوچ اور اپنی فکر ہے یا کہیں سے انھوں نے کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے مستعار لی ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ بات اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ مرزا غلام احمد سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسی بات اگر عمار ناصر صاحب کے علم میں ہو جس کو بنیاد بنا کر ہم مسلمان انھیں اپنے قریب لا کر دین اسلام کی دعوت دے سکیں تو وہ بتائیں۔ دعوت حق تو اسی وقت دی جائے گی جب دعوت حق کا ماحول باقی رہے گا۔ اگر دعوت حق دے کر انھیں قریب لانا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہمارے بزرگ یہ کام کرنا جانتے تھے اور انھوں نے یہ کوشش بھی کی جو رائیگاں گئی۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب بات حد سے گزر جائے تو پھر اس کا دوسرا علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھوڑا اگر کینسر بن جائے تو اسے جسم سے الگ کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ پورے جسم کے ختم ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ملت اسلامیہ نے قادیانیوں کے ساتھ کیا، یہی علاج بہتر تھا اور جو کچھ قادیانیوں کے ساتھ ہوا، اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں، قادیانیوں پر عائد ہوتی ہے۔ خود کردہ را علاجے نیست۔ قومی اسمبلی جس نے انھیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس کی ساری کارروائی موجود ہے جو میری اس بات کی ایک بین دلیل ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ قادیانیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا اور کیوں اختیار کیا کہ کوئی ایسی قدر باقی نہ رہی جس کو بنیاد بنا کر ہم وہ کام کر سکتے جس کی خواہش نے عمار ناصر صاحب کی راتوں کی نیند اور دن کا چین ان سے چھین لیا ہے۔
اگر ان تمام باتوں کے باوجود عمار ناصر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن تھا، لیکن کیا نہیں گیا تو پھر انھیں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اب وہ خود اس نیک کام کا آغاز کر دیں۔ انھیں کون روک رہا ہے؟ وہ قادیانیوں کے ساتھ معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، معاشی تعلقات استوار کرنے کا آغاز کریں۔ کوئی ایسی تنظیم بنا لیں تو زیادہ منظم طریقے سے بھی یہ نیک کام ہو سکتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے کہ کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے، کر گزرنا مشکل ہے۔
عمار خان ناصر صاحب نے ماہنامہ ’’اجتہاد‘‘ کے صفحہ ۸ پر جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، وہ تو انتہائی قابل اعتراض ہیں جس میں انھوں نے قادیانیت کے خلاف امتناعی قوانین اور توہین رسالت کی سزا کو محض عوامی سطح پر پائے جانے والے جذبات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ’’یک رخے انداز فکر‘‘ کا نتیجہ بتایا ہے۔ میرے خیال میں جب وہ یہ انتہائی قابل اعتراض سطور تحریر کر رہے تھے تو وہ خود اسی جذباتی کیفیت میں مبتلا تھے جس کا وہ ہمیں طعنہ دے رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ ’’جذبہ‘‘ فی نفسہ کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی شے ہے۔ جذبات سے عاری انسان تو ان صفات کا سرے سے متحمل ہی نہیں ہو سکتا جو شخصیت کی تکمیل اور انسان کہلانے کے لیے ضروری اور لازمی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جذبہ مثبت ہے یا پھر منفی۔ یہ دونوں پہلو اگر ساتھ ساتھ رہیں تو جذبہ کار خیر کے لیے ایک تحریک پیدا کرتا ہے۔
آزادی کی مثال سے بات مزید واضح ہوتی ہے۔ آزادی کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک منفی اورایک مثبت۔ منفی پہلو میں ایک فرد کو کچھ کاموں سے روک دیا جاتا ہے اور مثبت پہلو کے ذریعے ایک فرد کو کچھ کاموں کی آزادی ہوتی ہے۔ اگر آزادی کا منفی پہلو نظر انداز کر دیا جائے تو آزادی مادر پدر آزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کانقصان پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر جذبہ صحیح جگہ پر صحیح کام کر رہا ہے تو پھر جذبہ مضر نہیں رہتا، کیونکہ اس کا مثبت پہلو منفی پہلو پر غالب رہتا ہے۔ ایسا جذبہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور اگر جذبہ غلط کاموں کا محرک بن جائے یعنی مثبت پہلو سے ہٹ کر منفی پہلو کو پیش نظر رکھے تو پھر جذبہ مضر ہے۔ اس لیے جناب عمار ناصر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کے جذبات نے انھیں صحیح کام کرنے پر آمادہ کیا ہے تو یہ کام کوئی غلط کام نہیں تھا جسے نشانہ تنقید بنایا جائے۔
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی کمان ابوجہل کے سر پر مار کر اسے زخمی کر دیا تھا تو وہاں پر بھی جذبہ ہی تھا جو اس کا محرک بنا اور اگر ابوجہل نے اپنے آخری وقت میں اپنا سر قلم کراتے ہوئے یہ کہا تھاکہ سر ذرا اوپر سے کاٹنا کہ سردار کا سر نیزے پر اونچا نظر آئے تو یہاں بھی جذبہ ہی ہے۔ اب دونوں جذبوں میں جو فرق ہے، وہ واضح ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے قادیانیوں کے خلاف جو کچھ بھی کیا، وہ بھی جذبہ ہی ہے، لیکن یہ جذبہ مثبت ہے، منفی نہیں۔ یہ جذبہ حضرت حمزہؓ سے لیا گیا ہے، ابو جہل سے نہیں۔ یہ سب کچھ محض عوامی جذبات نہیں، بلکہ عالم اسلام اس بات کا معتقد ومعترف ہے کہ جو کچھ ہوا، ہونا چاہیے تھا اور قادیانیوں کو ان کی اصل جگہ پر لا کھڑا کرنا ضروری تھا۔ یہ ملت اسلامیہ کی ایک ایسی کامیابی ہے جس پر آنے والی نسلیں ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی۔ اب کوئی دعواے نبوت کرے گا تو اسے پھلنے پھولنے کا وہ موقع میسر نہیں آئے گا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو آیا۔ یوسف کذاب کی مثال آ پ کے سامنے ہے۔ یہ انھی امتناعی احکامات کا نتیجہ ہے کہ اب قادیانی اسلامی شعائر کو استعمال کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ان بھولے بھالے قادیانیوں پر ترس کھانے کے بجائے ان بھولے بھالے مسلمانوں پر ترس کھانا شروع کریں جو قادیانیوں کی تخریب کاری سے اب بھی اس طرح محفوظ نہیں جس طرح ہونا چاہیے کہ اب بھی لالچ، دھوکا، فریب کے طریقوں سے قادیانی مسلمانوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں، اگرچہ امتناع قادیانیت آرڈیننس نے ان کے لیے یہ کام بہت مشکل کر دیا ہے کہ اب شکاری، شکاری کے لباس میں ہے، دین کے مبلغ کے لباس میں نہیں۔
قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر کے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں جیساکہ اس غیر اسلامی ریاست میں دوسرے مذاہب کے لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو مسلمان بن کر یا مسلمان کہلا کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے دینا کس لحاظ یا کس پہلو سے درست ہے کہ آپ امتناعی قوانین کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آخر میں ہم جناب عمار خان ناصر صاحب کو اپنے خیالات پر دوبارہ سوچنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ اکابرکی قربانیوں اور شہداے ختم نبوت کے خون سے غداری کے مترادف ہے جو ایک دینی گھرانے کو زیب نہیں دیتی۔
آپ نے اپنے رسالے میں بھی کسی کے ایک سوال کے جواب میں جو کچھ تحریر کیا ہے، وہ بھی آپ کے انھی خیالات وجذبات کا عکس ہے جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ جواب کا وہ حصہ نذر قارئین ہے:
’’قادیانی قیادت اور ان کے تاویلاتی جال میں پھنس جانے والے عام سادہ لوح مسلمانوں کے مابین جو فرق حکمت دین کی رو سے ملحوظ رکھا جانا ضروری تھا، وہ نہیں رکھا گیا اور عام لوگوں کو ہمدردی اور خیر خواہی سے راہ راست پر واپس لانے کے داعیانہ جذبے پر نفرت اور مخاصمت کے جذبات نے زیادہ غلبہ پا لیا۔ میرے نزدیک قادیانی گروہ کو قانونی طور پر مسلمانوں سے الگ ایک غیر مسلم گروہ قرار دے دیے جانے سے امت مسلمہ کے تشخص اور اس کی اعتقادی حدود کی حفاظت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے علما اور داعیوں کی محنت اور جدوجہد کا ہدف اصلاً یہ ہونا چاہیے کہ وہ دعوت کے ذریعے سے ان عام قادیانیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے حوالے سے قادیانی قیادت کا مفاد بھی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں سے الگ تھلگ اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ناواقف رہیں اور معلوم نہیں کن ضرورتوں یا مجبوریوں کے تحت ہماری مذہبی قیادت بھی انھیں مسلمانوں سے دور ہی رکھنے کو اپنی ساری جدوجہد کا ہدف بنائے ہوئے ہے۔ ‘‘
اس پر میں اب کیا تبصرہ کروں! انتہائی افسوس کے ساتھ یہ شعر ہی پیش خدمت ہے۔
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
مکاتیب
ادارہ
(۱)
محترم ومکرم جناب زاہدالراشدی صاحب زیدت معالیہ
السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ،
الشریعۃ بابت جولائی ۲۰۱۱ء میں مولانا محمد عیسیٰ منصوری صاحب کے مضمون بعنوان ’’دعوت اللہ کا فریضہ اور ہمارے دینی ادارے‘‘ کی دوسری قسط کا مطالعہ کیا۔ اگرچہ پہلی قسط ابھی تک نظروں سے نہیں گزری، لیکن اسی قسط سے پہلی قسط کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مولانا محترم کے اس مضمون کا خلاصہ یہ لگتا ہے کہ یہ اُمت دعوت ہے! یہ بات سو فیصدی سچ ہے، لیکن اس بات کو موجودہ عالمی تناظر میں جس انداز سے پیش کیا گیاہے، اُس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیش کرنے والا نہ صرف جہاد کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کررہا ہے بلکہ اس کو اُمت کی تباہی اور بربادی کا سبب قرار دے رہا ہے۔ سو اس فکر سے ہمیں شدید اختلاف ہے۔ گودعوت اسلام کی توسیع میں اصل کا رگر قوت ہے، لیکن اسلام سمیت کوئی نظریہ اور موقف ایسا نہیں جس کو اپنے مخالفین سے مخالفت بلکہ تصادم کا خطرہ نہ ہو۔ اسلام کتنا ہی فطری اور اپنے ہی ضمیر کی آواز کیوں نہ ہو، لیکن انسانی نفسیات کا یہ مسلمہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ معاشرے کے جن طبقات کے مقام ومرتبے اور مفادات پر اس کی زد پڑتی ہے، وہ نرے وعظوں اور اخلاقی اپیل سے اس کا راستہ روکنے سے ہر گز باز نہیں آئیں گے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر حکیم اور انسانیت کا خیر خواہ نسل آدم میں کوئی ہوگا؟ لیکن اُن کو بھی اسی ضرورت سے ہتھیار اٹھانے پڑے۔ پھر سخت حیرت ہے اُن لوگوں پر جو نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور انھی کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی اسلام کی ایک ایسی ناقابل فہم اور ناقابل عمل تخیلاتی تعبیر پراصرار کررہے ہیں جو چودہ سو سالہ تاریخ میں اسلام کی کسی بھی مستند شخصیت کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔
دعوت اور جہاد دونوں اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں اور سخت غلطی کر رہے ہیں وہ لوگ جو دعوت کی اہمیت کے بیان میں جہاد کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاد نے ہمیشہ مسلمانوں کو عزت اور وقعت کا مقام دیا ہے۔ یہ ترک جہاد کا ثمرہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ کے لیے کفر کی بدترین غلامی میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ سخت حیرت ہے کہ جہلا نہیں، بڑے بڑے خبردار اور علما قسم کے لوگ اس مہم میں بری طرح جتے ہوئے ہیں کہ اسلام دعوت کا مذہب ہے، جہاد کا نہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ان کے پیش نظر نہیں ہے کہ"الجھاد ماض الی یوم القیمۃ‘‘؟ کیا اس میں کسی بھی دور کا استثنا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں خواہ مخواہ کھینچ تان کر موجودہ دور کو اس سے نکال رہے ہیں؟ اور کیا یہ حدیث بھی کبھی کانوں سے نہیں ٹکرائی کہ ایک زمانہ آئے جب ’’قرا‘‘ قسم کے لوگ کہیں گے کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں۔ حضورعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم ایسی بات سنو تو سمجھ لو کہ وہی جہاد کا زمانہ ہے۔ کسی نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ایسی بات کہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہا ں وہ شخص جس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ؐ کی پیشین گوئیوں کے کہ جو الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، وہی الفاظ آج بڑے بڑے دینداروں کے منہ سے بعینہ نکل رہے ہیں اور کہا جارہا ہے کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے۔
قرآن کی آیات اور روایات حدیث سے تو بصراحت جہاد کی سخت ضرورت واہمیت معلوم ہورہی ہے اور ایک دُنیا اچانک جہاد کے خلاف اُٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ اُس کفر کا ایک مظہر تو نہیں جو عالم اسلام کے چپے چپے میں دکھائی دے رہا ہے؟ عام طور پر کفر اور خصوصاً دورحاضر کا کفر کتنے طریقوں اور حیلوں بہانوں سے ہمارے ذہنوں میں ایسے افکار انڈیل رہا ہے جو اُس کی عالمی بالا دستی اور مسلمانوں کی پستی وتنزل کاسبب بن رہے ہیں اور ہم سب بالخصوص ہمارا دانشوراور روشن خیال طبقہ انہی خیالات کو نئے رنگ وروغن کے ساتھ اُمت مسلمہ میں پھیلا رہا ہے۔ یورپ خود تو خون کی ندیا ں بہارہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ نظریے کی خاطر ہتھیار اُٹھانا دہشت گردی ہے۔
میں قرآن وحدیث کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ آج کل پشاور کے ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ کسی زمانے میں مختلف رسائل میں تھوڑی بہت لکھنے کی عادت تھی، لیکن عرصہ ہوا یہ سلسلہ چھوٹ گیاہے ، لیکن جہاد کے خلاف اس عالمی مہم نے مجھے سخت بے قرار کردیا ہے۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ چل پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے دین کے بارے میں بہت توقعات تھیں، لیکن اب یہ دیکھ کر سخت کوفت ہوتی ہے کہ یہ پوری جماعت جو مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اصاغرواکابر سب بلاتفریق جہاد کے خلاف کمر بستہ ہیں اور جہا د کو فساد باور کرارہے ہیں اور جرات اور بے باکی اس حد تک پہنچی ہے کہ چونکہ قرآن وحدیث سے جہاد کے مضمون کوکھر چا نہیں جاسکتا، سو وہ قرآن وحدیث کے حلقوں کو خاموش اور موقوف کرنے کی شعوری کوششوں میں ہمہ تن مصروف ہیں اور ان کے بارے میں بہت ناگفتنی باتیں بنا رہے ہیں ۔ مثلاً یہ کہ ہم تو جوڑ پیدا کر رہے ہیں اور قرآن توڑ پیدا کررہا ہے۔ آپ بتائیں، یہ کافرانہ باتیں نہیں ہیں؟ قرآن وحدیث کی جگہ تبلیغی نصاب اورفضائل اعمال کو رواج دے رہے ہیں اور جو صریح آیات واحادیث قتال کے بارے میں ہیں، اُن میں سخت مجرمانہ تحریف کرکے بستر اٹھانے پر فٹ کر رہے ہیں۔ قرآن وحدیث سے تھوڑی سی شناسائی رکھنے والا بھی ایمانداری سے کہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہے یا کفر کی؟ انگریزوں نے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا تصور محو کرنے کے لیے ایک جعلی نبوت تیار کی، لیکن وہ مہم کچھ زیادہ کا میاب نہیں ہوسکی۔ اب کی بار اُنہوں نے تیر صحیح نشانے پر مارا ہے۔ مسلمانوں کی ایک عالمی جماعت کو پتہ نہیں، کس طرح سے جہاد کے خلاف کھڑا کیا اور مشرق ومغرب کے ان گنت مسلمان دانشوروں کو اُن کی فکری اور علمی مدد اور نصرت پر لگا دیا۔ یقیناًیہ مہم کسی درجے میں کامیاب ہوگی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ جہاد کی برکت سے کفر کی کمر ٹوٹنے والی ہے اور مسلمانوں کا دور عروج دستک دے رہا ہے، کافر اور ان کے ایجنٹ یا اسلام کے احمق ترین دوست پورے زورو شور سے جہاد کے خلاف صف بندی کیے ہوئے ہیں۔ آج جہاد کے خلاف مہم چلانا ایسا ہے جیسے مجاہدین اسلام کی پیٹھ میں پیچھے سے چھرا گونپنا۔
مجھے مولانا منصوری سے شخصی تعارف بالکل نہیں۔ آج سے چار پانچ سال پہلے اُن کا ایک مضمون ’الحق‘ اکوڑہ خٹک میں چھپا تھا۔ اُس کو میں نے پڑھا تھا۔ اُس میں اسلام کی احیائی تحریکوں کے خلاف مواد تھا۔ اُس وقت بھی اس مضمون پر شدید تحفظات پیدا ہوئے تھے اور آج پھر اسی فکر کو نئے انداز میں الشر یعہ میں پڑھا۔ اگرچہ اُن کے مضامین میں کام کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اُن کے بنیادی فکر سے ہمیں شدید اختلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بقول اُن کے اگر اُمت نے ماضی میں دعوت کے کئی مواقع ضائع کرکے نقصان کیا ہے تو آج جہاد کا انکا رکرکے ملت کو اس سے کہیں بڑھ کر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آج اُمت کو جہاد کی ضرورت ہے۔ افغانستان اور دُنیا کے بعض دیگر ملکوں میں کفر واسلام کا معرکہ برپاہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کی عظیم قوتوں اور بالخصوص حیرت انگیز ٹیکنالوجی کی طاقتوں کے توڑ کے لیے تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ پر عزم اور پرجوش مجاہدین کو لا کھڑا کیا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کو ان مجاہدین کی دامے درمے سخنے مدد کرنی چاہیے، نہ یہ کہ کفر کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوکر ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔
الطاف الرحمن بنوی
اُستاد جامعہ امداد العلوم، پشاور صدر
(۲)
ماہنامہ الشریعہ جولائی ۲۰۱۱ء کے ص۱۱ تا ۲۵ پر روشن خیالی سے بھرپور ایک مضمون بعنوان ’’سماجی، ثقافتی اور سیاسی دباؤ اور دین کی غلط تعبیریں‘‘ شائع ہوا ہے جسے پڑھ کر خیال گزرا کہ مولانا وحید الدین خان، جناب ذاکر نائیک، جناب جاوید غامدی اور اسی قبیل کے روشن خیال، جدید مفکرین اور اسکالرز ہی کے تسلسل کا نام حافظ صفوان محمد چوہان ہے۔ مندرجہ بالا دینی اسکالرز سے اختلاف رائے کے باوجود ہمارے دل میں ان کا ادب و احترام ہے۔ ان کے تفرد و تجدد سے قطع نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے میدان کی قد آور شخصیات ہیں اور ان کی مثبت خدمات سے انکار کی کوئی صورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حافظ صفوان کس بنیاد پر اپنا قد بڑھانے کے لیے یہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں، یہ معاملہ ہماری فکرا ور سوچ سے ماورا ہے۔ گلاب جامن اور رس گلے میں جو زہر چھپا کر انہوں نے اس مضمون کے ذریعے عوام الناس کو دیا ہے، اس کے نتائج انتہائی بھیانک نکلیں گے۔ شراب کی بوتل پر زم زم کا لیبل چپکانا اور سور کے گوشت کو بکری کے گوشت سے تعبیر کرنا، یہ انداز بہت ہی خطرناک و المناک ہے۔
حافظ صفوان کا طریقہ بھی عجیب غریب ہے۔ کبھی تبلیغی جماعت کی آڑ لینا اور کبھی مجلس احرار اسلام کا نام لے کر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرنا، چہرے پر ڈاڑھی سجا کر اور سر پر ٹوپی اوڑھ کر ڈاڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے والوں کا مذاق اڑانا، یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے طرز فکر کو اپنانے جیسا فعل ہے۔ فکری و ذہنی انتشار کی عکاس یہ طویل تحریر پڑھ کر صفوان چوہان صاحب کے ژولیدہ فکر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ تضادات کا مجموعہ یہ تحریر معلوم نہیں، انہوں نے کس ترنگ میں آ کر لکھی ہے۔ دینی مزاج، دینی ذوق اور دینی انداز فکر رکھنے والوں پر انہوں نے جو دست تطاول دراز کیا ہے، یہ ان کے چرغینہ پن پہ دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے جس چترائی سے دینی حلقوں پہ ہاتھ صاف کیا ہے، اسے پڑھ کر ہم انگشت بدنداں رہ گئے کہ یہ وہی حافظ صفوان چوہان ہیں جو پروفیسر عابد صدیق مرحوم جیسے ولی اللہ کے بیٹے تھے، یہ وہی ہیں جو نواسۂ امیر شریعت، سیدذوالکفل بخاری شہید کے دوست تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے ماہنامہ الاحرار کی خصوصی اشاعت میں رئیس المبلغین حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پر مضمون لکھا تھا؟ یا یہ کوئی روشن خیال اور جدت پسند قسم کے کوئی صفوان چوہان ہیں۔ معلوم نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے اور کس سے اشیرباد حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے یہ طرز تحریر اپنایا ہے۔
عورتوں کا دکانداری کرنا، عورتوں کا مسجد میں آ کر نماز باجماعت میں شریک ہونا، اس کے دلائل دینا، اسلامی لباس کا تمسخر اڑانا، دینداری کو جہالت سے تعبیر کرنا، دینی و معاشرتی زرّیں اقدار کو دیرینہ اسلامی لطیفہ قرار دے کر ان کا مذاق اڑانا، برقعے اور پردے پہ تنقید، مساجد کو کمیونٹی سنٹرز سے تعبیر کرنا، تحریک آزادی کے نامور رہنماؤں پہ غصہ نکالنا ، سر سید احمد خان کو سیدالقوم، سر آغا خان کو قومی و ملی تاریخ کے ڈیڑھ ہزار سالہ سفر میں آنے والی کہکشاؤں میں سے ایک بڑا نام اور انہیں ستاروں کے لیے نشان راہ قرار دینا، اقبال شکنی، قائد اعظم شکنی اور سر سید شکنی کے نام پر اہل حق سے اظہارِ بے زاری، علمائے حق کے مقام، مرتبہ اور عزت و عظمت پہ تنقیدات، یہ سب آخر کیا ہے اور کس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ تحریک آزادی کے نامور قائدین، جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام کے جانفروش رہنماؤں کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں، آج ان کی کیا عزت ہے، ان کو آج کون جانتا ہے، یہ گھناؤنا انداز اور یہ پھکڑ بازیاں کس مکروہ اور کثیف سوچ کی عکاس ہیں؟
حافظ صفوان چوہان صاحب! سید ذوالکفل بخاری شہید کوئی صدیوں پرانے بزرگ نہیں۔ اُن کی حادثاتی وفات کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ مرحوم نے عرصۂ حیات کسی گمنام مقام پر نہیں گزاراکہ اُنھیں آپ کے علاوہ کوئی جانتا نہ ہو۔ میرے خیال میں آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جتنے انسانوں سے آپ کو ساری زندگی میں ملاقات کا موقع ملا ہے، مرحوم کے صرف مستفیدین کا حلقہ ہی تعداد میں اس سے وسیع تر ہے۔ مرحوم ایک صالح نوجوان تھے، اسکول و کالج بلکہ کسی ماحول میں بھی وہ سر سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے۔ ایک بار کلاس ٹیچر نے جب اس حوالہ سے سختی کی تو انہوں نے اپنا سیکشن تبدیل کرا لیا تھا، مگر سر سے ٹوپی اتارنا گوارا نہ کیا۔ آپ اپنا ہودہ و بے ہودہ ان کے نام منسوب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واہیات ارشاد فرمانے ہی ہیں تو براہ کرم کسی اور کندھے کو تلاش کیجیے۔ الفاظ آپ کے، سوچ آپ کی اور منسوب کر رہے ہیں سید ذوالکفل بخاری شہید کی طرف! یہ دوست کشی اور محسن کشی کی انتہا ہے۔ کیا اس سے آپ کا انکار ممکن ہے کہ آپ اپنی تحریرات میں ان سے رہنمائی لیتے تھے اور آپ کی باگیں اُنھی کے ہاتھ میں تھیں؟ بلا شبہ اُن کے انتقال کے بعد آپ بے پیر ے ہو گئے ہیں۔
آپ کا یہ فرمانا کہ ’’پتلون کو ٹھیٹھ فرنگی لباس سمجھنا بھی راہ اعتدال سے ہٹ جانا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی اسلامی فوج کے یونیفارم کی وضع یہی رہی ہے۔۔۔۔۔۔ٹائی کو صلیب سمجھنا بھی ایک دیرینہ اسلامی لطیفہ رہا ہے‘‘۔ آپ کے مضمون کی ہر سطر کا ہر لفظ شاہد عدل اور شاہد اہل ہے کہ نہ تو آپ کو مذہب کے بارے میں مطالعے کا موقع ملا ہے اورنہ ہی تاریخ سے آپ کو کچھ مس ہے۔ آپ تو نرے پروفیسرو ڈاکٹر ہیں، بلکہ اب تو اِس دال میں بھی کچھ کالا محسوس ہوتا ہے۔ اب آپ جس راہ اعتدال پہ قوم کو لانے کی سعی لاحاصل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پرویز مشرف اور آپ کی سوچ میں کتنی مماثلت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔
’’برقعے والی جھانپو کبوتری‘‘ یہ کیا اصطلاح ہے؟ یہ واہیات لفظ چیخ چیخ کر پکاررہاہے کہ آپ ہی کے دہن شریف سے نکلا ہے اور یہ اصطلاح پیش کر کے برقعہ اوڑھنے والی عورتوں کے لیے آپ کس نئے نام کو متعارف کر وا رہے ہیں؟ آپ کی اس تحریر کو پڑھ کر اگر کل کوئی منچلا کسی برقعہ پوش عورت کو ان الفاظ سے پکارے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہی ہوں گے! آپ اپنے اس ارشاد گرامی پر بھی غور فرمائیں کہ ’’عورتوں کو برقعے میں اتنا چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں پہچانا ہی نہ جا سکے‘‘ اور یہ بھی کیا طرفہ ارشاد ہوا ہے کہ ’’برقعے کا مقصد زینت کو چھپانا ہے نہ کہ عورت کی شناخت کو چھپانا‘‘ اور ساتھ ہی فتویٰ بھی دے دیا کہ ’’ شناخت کو چھپانا شرعاً اور قانوناً جرم ہے۔‘‘ شریعت اور قانون میںیہ در اندازی انتہائی واہیات ہے۔ جنابِ من! اپنی حیثیت کا تعین کر لیجیے۔آپ کے جُلسا سے سُنا ہے کہ آپ علم و جہل کے سیاق میں خود ہی بتایا کرتے ہیں کہ آپ کے تو بیٹے کا نام بھی عکرمہ ہے۔ ’’وطن کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔‘‘ عربی کے اس مقولہ کو حدیث پاک کے الفاظ قرار دینے کی جرات عکرمہ کے ابو ہی کر سکتے ہیں۔ ’’پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہ ہونے والی جماعت‘‘ کا طنز آپ نے کس جماعت پر کیا ہے اور اس جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟
آخری التماس آپ سے یہ ہے کہ براہ کرم سید ذوالکفل بخاری شہید کے علوم و افکار کے وارث اور شارح آپ نہ بنیں، اپنے نظریات کے پرچار کے لیے ان کا نام استعمال نہ کریں، امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و افکار کے شارح پروفیسر محمد سرور بنے اور انہیں ایک متنازعہ شخصیت بنا دیا۔ اب آپ سید ذوالکفل بخاری شہید کے شارح بن کر براہ کرم انہیں متنازعہ نہ بنائیں۔وہ بہت محترم انسان تھے۔شہادت کے بعد تو اور زیادہ لائق احترام ہو گئے ہیں۔ آپ اگر ان کا احترام نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن ایسی واہیات اور مکروہ باتیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کی روح مبارکہ کو اذیت تو نہ پہنچائیں اور اُن کے چاہنے والوں کی دل آزاری بھی نہ کریں۔ اسی میں آپ کا بھلا ہے۔
افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی
خوفِ فسادِ خلق سے ناگفتہ رہ گئے
محمد عکاشہ سرور۔ ہری پور
(۳)
ماہنامہ الشریعہ کے جولائی ۲۰۱۱ء کے شمارے میں ڈاکٹر حافظ صفوان محمد چوہان کا مضمون نظر سے گزرا۔ حافظ صفوان صاحب نے نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، اعتکاف سے لے کر لباس، برقعہ، عدت، نکاح، تصویر، کرنسی کی قدر وقیمت اور قرض تک کئی موضوعات کا نہایت خوب صورتی سے تجزیہ پیش کیا ہے۔ زندگی کے عملی احوال سے متعلق ایسے حساس موضوعات پر ایک ہی مضمون میں حق ادا کرنے کی کوشش بجاے خود قابل تحسین ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ صفوان صاحب نے اپنے مخصوص اسلوب بیان سے قارئین کے دل موہ لیے ہیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر اکرم ورک صاحب بتا رہے تھے کہ انھوں نے اس مضمون کی بنیاد پر اپنی مسجد میں چار دروس دیے ہیں۔ اسی طرح الشریعہ کے ایک او ر قاری نے فرمایا کہ جب سے انھوں نے ’الشریعہ‘ کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، اس وقت سے اب تک یہ مضمون انھیں بہترین مضمون معلوم ہوا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صفوان صاحب کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مخصوص طور اطوار نے دین کی غلط تعبیریں دین کے سر منڈھ دی ہیں۔ رمضان المبارک میں روزوں کی کیفیت کو ہی دیکھ لیجیے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو کثرت مواقع کے باوجود چھپ چھپا کر کھا پی لیتا ہو۔ اسی طرح شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کے رویے میں کھانے پینے سے پرہیز کے علاوہ کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جھوٹ بولنے سے، بدنظری سے، بد عنوانی سے، لوٹ مار کرنے سے اور بدکلامی سے بھی روزہ، روزہ نہیں رہتا۔ یہاں بھی دین کی غلط تعبیر کام کر رہی ہے کہ اللہ روزے کے دوران میں کھانے پینے سے تو ناراض ہوتا ہے، لیکن دیگر کرداری امور سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، یعنی عملاً بس کھانے پینے سے پرہیز ہی حقیقی روزہ ہے۔ حافظ صفوان صاحب کے تتبع میں، میں بھی قارئین الشریعہ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ روزہ اپنی اصل روح کے ساتھ ہمارے ہاں آخر کب جلوہ گر ہوگا؟
پروفیسر میاں انعام الرحمن
inaam1970@yahoo.com
(۴)
Brother Ammar Sahib, Assalaam-o-alaikum.
I have read with keen interest the letters of Brothers Izhar and Zahid Mughal. I really appreciate the efforts of Al-Sharia in accommodating different, even opposite, opinions. Arguments are always good, but discussions between various schools of thought are best. I think argument is to find who is right but discussion is to know what is right. Lets say this is the main objective of Al-Sharia. Therefore I cannot endorse what Brother Izhar said about not publishing the views which he thinks are not correct.
However I could not justify the remarks of Brother Zahid Mughal that other people do not understand about science and technology and he is the only person who has perceived the actual understanding of Western or even Greek Philosophy. His own opinion about Western Philosophy or Science may be true according to his knowledge but I have no right to say that he jumps in to draw wrong conclusion without studying basic issues of philosophy of science, theory of knowledge etc.
If I am not bracketed or blended with an Ignorant Muslim or a modern man whose science is the deity, I think distinction can be made between science and technology and their results without the West as a cultural value system, which Mr. Mughal failed or did not like to perceive. I do not wish to horn with anybody over this issue but I see my religion and science as compatible and wish to bring all scientific investigations within the realm of Islam. Rather let me put bluntly that Islam flourish more within a scientific atmosphere than in a closed and one-sided blind society.
I agree that the materialistic philosophy, which set the agenda and goals for Western science and technology, produced corrupted results due to evil intentions. However correct intentions as proffered by Islam would permit the proper use of science and technology. Therefore it is utmost necessary that Muslims should study and use modern science and other social sciences without which I am afraid our future is dark.
M. Anwar Abbasi
anwarabbasi@hotmail.com
اکتوبر ۲۰۱۱ء
توہین رسالت کی سزا پر جاری مباحثہ ۔ چند گزارشات
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
توہین رسالت پر موت کی سزا کے بارے میں امت میں عمومی طور پر یہ اتفاق تو پایا جاتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے لعین وشقی شخص کی سزاموت ہی ہے، مگر اس کی فقہی اور عملی صورتوں پر فقہاے امت میں اختلاف ہر دور میں موجود رہا ہے کہ مسلمان کہلانے والے گستاخ رسول کو موت کی یہ سزا مستقل حد کی صورت میں دی جائے گی یا ارتداد کے جرم میں اسے یہ سزا ملے گی اور اس کے لیے توبہ کی سہولت وگنجائش موجود ہے یا نہیں؟ اسی طرح غیر مسلم گستاخ رسول کو یہ سزا تعزیر کے طور پر دی جائے گی یا اس کی فقہی نوعیت کچھ اور ہوگی اور ایک ذمی کا عہد اس قبیح جرم کے ارتکاب کے بعد قائم رہ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ ان اختلافی صورتوں پر ہمارے دور کے علماے کرام کے درمیان بھی بحث وتمحیص کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف دینی جرائد میں ان عنوانات پر تحقیقی مضامین شائع ہو رہے ہیں۔
’’الشریعہ‘‘ کے آغاز سے ہی ہمارا یہ ذوق اور موقف چلا آ رہا ہے کہ اس نوعیت کے مسائل پر علمی مباحثہ کھلے دل کے ساتھ ہونا چاہیے اور کسی مسئلہ کے تمام پہلو اہل علم کے سامنے رہنے چاہییں تاکہ انھیں راے قائم کرنے میں آسانی ہو۔ ’’الشریعہ‘‘ خود اس قسم کے مباحثوں کا مستقل فورم ہے جس پر ہمیں بعض حلقوں کی طرف سے طعن واعتراض بلکہ بعض مواقع پر طنز واستہزا کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم ایسے مسائل پر کھلے علمی وتحقیقی مباحثہ کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری رکھنے کے موقف وعزم پر قائم ہیں۔
مذکورہ مسئلہ پر ملک کے جن اہل علم نے سنجیدگی سے قلم اٹھایا ہے، ان میں دیگر علماء کرام کے علاوہ مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی، مولانا عبد القدوس خان قارن، مولانا مفتی ڈاکٹر عبد الواحد، مولانا مفتی محمد زاہد، علامہ خلیل الرحمن قادری، ڈاکٹر حافظ حسن مدنی، پروفیسر مشتاق احمد اور حافظ محمد عمار خان ناصر بطور خاص قابل ذکر ہیں اور ہم ان سب حضرات کے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ایک علمی مباحثہ کو آگے بڑھانے کی طرف توجہ دی اور اس میں حصہ لیا، البتہ اس مباحثہ کے حوالے سے راقم الحروف کے کچھ ذاتی تحفظات ہیں جن کی طرف ارباب علم ودانش کو توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔
پہلی گزارش یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے لعین شاتم رسول کے لیے توبہ کی گنجائش کے مسئلہ پر علامہ ابن عابدین شامیؒ نے اب سے پونے دو سو برس قبل خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ چونکہ ارتداد ہے اور کسی بھی مرتد کے لیے توبہ کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے اسے ارتداد کے احکام کے تحت توبہ کا موقع ملنا چاہیے اور متقدمین حنفی فقہا کا موقف بھی ابن عابدین شامیؒ کے بقول یہی ہے۔ حالیہ مباحثہ میں ہمارے ایک فاضل دوست نے اسے علامہ شامی کا ’’تسامح‘‘ قرار دیا ہے اور دوسرے فاضل دوست نے اسے ’’مغالطہ‘‘ کہہ کر علامہ شامی کے موقف کو پس منظر میں لے جانے کی کوشش کی ہے۔
راقم الحروف کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ علامہ شامیؒ نے یہ بات چلتے چلتے کسی جگہ سرسری انداز میں نہیں کی، بلکہ اسے مستقل موضوع بحث بنا کر اس پر کلام کیا ہے اور اس پر تفصیلی دلائل پیش کیے ہیں۔ مثلاً انھوں نے ’’شرح عقود رسم المفتی‘‘ میں لکھا ہے کہ بعض مسائل عام طور پر احناف کے موقف کے طور پر مشہور ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ احناف کا موقف نہیں ہیں۔ ان میں علامہ شامی نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ احناف کے ہاں شاتم رسول کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ احناف اسے ارتداد سمجھتے ہیں اور مرتد کے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ پھر علامہ شامی نے اپنی کتاب ’’العقود الدریۃ فی تنقیح الفتاویٰ الحامدیۃ‘‘ میں یہ مسئلہ بیان کیا اور اس پر اس وقت کے مفتی حمص علامہ عبد الستار آفندیؒ نے کچھ اشکالات پیش کیے تو ان کے جواب میں علامہ شامیؒ نے ’’تنبیہ الولاۃ والحکام‘‘ کے نام سے مستقل رسالہ لکھا جس میں انھوں نے پوری وضاحت اور دلائل کے ساتھ یہ موقف پیش کیا ہے۔ یہ بات بطور خاص قابل توجہ ہے کہ علامہ شامیؒ نے، جو خلافت عثمانیہ کے دور میں احناف کے سب سے بڑے ترجمان اور مفتی تھے، حتیٰ کہ گزشتہ ڈیڑھ صدی سے ہمارے ہاں پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور بھارت پر مشتمل پورے خطے میں حنفی مفتیان کرام (دیوبندی اور بریلوی دونوں) کے فتاویٰ کا سب سے قریبی اور بڑا ماخذ وہی چلے آ رہے ہیں، انھوں نے یہ رسالہ ’’تنبیہ الولاۃ والحکام‘‘ کے عنوان سے لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے حکام سے مخاطب ہیں اور قانون سازی اور حکومتی پالیسی کے حوالے سے ان کی راہ نمائی کر رہے ہیں۔
علامہ شامی نے اپنے موقف کی حمایت میں جو تفصیلی دلائل دیے ہیں، وہ اس رسالہ میں پڑھے جا سکتے ہیں، مگر ہم اس سلسلے میں تفصیلات میں جانے کی بجائے صرف دو تین حوالوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ شامی اپنے موقف میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ بعض اکابر ائمہ احناف کی صریح حمایت بھی انھیں حاصل ہے۔ مثلاً امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج ص ۱۸۲ میں لکھا ہے کہ جو مسلمان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اس سے بائن ہو جاتی ہے، فان تاب والا قتل، اگر وہ توبہ کر لے تو فبہا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح امام طحاوی نے بھی مختصر الطحاوی ص ۲۶۲ میں یہی موقف بیان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک ایسا شخص مرتد ہے اور اس پر مرتد کے تمام احکام لاگو ہوں گے، جبکہ امام طحاوی ص ۲۵۸ پر مرتد کے احکام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ’فان تاب والا قتل‘، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔
یہ تو ائمہ احناف ہیں اور اگر اس سے ذرا پیچھے اور اوپر کی طرف نظر ڈالیں تو امام القیم نے زاد المعاد ج ۵ ص ۶۰ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی موقف ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:
ایما مسلم سب اللہ ورسولہ او سب احدا من الانبیاء فقد کذب برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ردۃ یستتاب فان رجع والا قتل
مجھے اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ یہ موقف ضرور قبول کر یں۔ آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے۔ اگر آپ دوسرے فقہاے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے دلائل پر اطمینان رکھتے ہیں تو اسے ترجیح دیں، لیکن ابن عابدینؒ کے موقف کو، جس پر انھوں نے تفصیلی دلائل دیے ہیں اور جس میں انھیں امام ابو یوسفؒ ، امام طحاویؒ اور سب سے بڑھ کر حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی صریح حمایت حاصل ہے، اسے ابن عابدین کا تسامح یا مغالطہ قرار دے کر اس کی علمی اہمیت کو کم کرنے کا آپ کو بہرحال حق حاصل نہیں ہے۔
دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایک انتہائی عزیز فاضل نے ابن عابدین شامی کے اس موقف کی حمایت کو ’’حنفیت کے نام پر غامدیت کی ترجمانی‘‘ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے جو خلاف واقعہ اور علمی دیانت کے خلاف ہے۔ جہاں تک جاوید احمد غامدی صاحب کا تعلق ہے، میں خود ان کے ناقدین میں سے ہوں۔ ان کے طرز استدلال واستنباط اور ان کے بعض نتائج فکر دونوں سے میں نے اختلاف کیا ہے اور اس پر نقد کیا ہے۔ ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ، روزنامہ اوصاف اسلام آباد اور روزنامہ پاکستان لاہور میں اس سلسلے میں میرے ایک درجن کے لگ بھگ مضامین شائع ہو چکے ہیں جو کتابی مجموعہ کی صورت میں الگ بھی طبع ہوئے ہیں، لیکن زیر بحث مسئلہ میں ’’غامدیت‘‘ کے حوالے سے گفتگو قطعی طور پر غیر متعلق ہے اور میں یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس، امام ابو یوسف، امام طحاوی اور ابن عابدین شامی کے موقف کو ’’غامدیت‘‘ قرار دینے سے ان بزرگوں کے موقف کا استخفاف مقصود ہے یا غامدی صاحب کو یہ کہہ کر حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، ان کا اختیار کردہ موقف اس قدر موثر بلکہ موثر بہ ماضی ہے کہ ان کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے کے ائمہ بھی ان کی حمایت کر کے گئے ہیں۔
غامدی صاحب کا جو موقف ماضی کے مسلمہ اہل علم سے مختلف ہے یا شریعت کے مسلمہ اصولوں کے منافی ہے، اس پر ضرور تنقید کیجیے۔ میں خود ان کے اور ان کے رفقاے فکر کے مختلف مضامین پر نقد کر چکا ہوں، لیکن اگر وہ ماضی کے مسلمہ اہل علم کی کسی بات کو اپنے موقف کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اسے ’’غامدیت‘‘ سے تعبیر کرنا علمی اور اخلاقی دونوں حوالوں سے محل نظر ہے۔ میں اس لہجے میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اگر یہ لہجہ ضروری سمجھ لیا گیا ہے تو میں اسے ’’غامدیت کے طعنے کی آڑ میں ائمہ احناف کے موقف کا استخفاف‘‘ قرار دینے کو ترجیح دوں گا جو بہرحال کسی صاحب علم کے شایان شان نہیں ہے۔
تیسری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اختلاف راے کے مختلف دائرے ہیں اور ہر دائرے کے الگ الگ احکام ہیں۔ مثلاً (۱) تکفیر (۲) تضلیل (۳) تفسیق (۴) تجہیل (۵) تخطۂ اور (۶) ترجیح کے مستقل دائرے ہیں جن کے الگ الگ تقاضے اہل علم کے ہاں مسلم ہیں اور ہر دور میں ان کا احترام کیا جاتا رہا ہے، مگر ہم نے ان مختلف دائروں کو اس طرح آپس میں گڈمڈ کر رکھا ہے کہ کچھ پلے نہیں پڑتا کہ کون صاحب کس دائرے کی بات کر رہے ہیں اور بسا اوقات
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی
کی کیفیت نظر آنے لگتی ہے۔ بات راجح ومرجوح کی ہوتی ہے اور ہم ناسخ ومنسوخ کے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، زیر بحث مسئلہ تعبیر وتشریح کا ہوتا ہے مگر ہم تکفیر وتضلیل کے ہتھیار اٹھا کر اس کا تیا پانچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صورت مسئلہ صواب وخطا کے دائرے کی ہوتی ہے، مگر اسے حق وباطل کا معرکہ بنائے بغیر ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ مثلاً شاتم رسول کے لیے توبہ کی گنجائش کے زیر بحث مسئلہ کو لیجیے۔ اگر اس میں متاخرین فقہا ے احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بھی لے لیا جائے کہ توبہ کی گنجائش نہیں ہے اور شاتم رسول کو ہر صورت میں قتل ہی کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ حضرت امام محمد کی طرف منسوب ایک قول بھی شامل کر لیا جائے تو بھی زیادہ سے زیادہ بات یہ ہوگی کہ احناف کے ہاں یہ راجح ومرجوح کا مسئلہ قرار پائے گا اور فقہاے زمانہ کے لیے دونوں طرف کی گنجائش موجود ہوگی کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، لیکن ہمارے ہاں یہ بحث کفر واسلام کے معرکہ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اختلاف کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس لادینیت اور گمراہی سے کم کوئی فتویٰ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بات جس درجہ اور سطح کی ہو، اسے اسی دائرے میں رکھا جائے تو اس کا حسن اور وزن دونوں ہر صاحب نظر کو محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر طعن وتشنیع اور الزام تراشی کے تیز مسالوں کے ساتھ اسے چٹخارہ دار بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کا حسن اور وزن، دونوں ان چٹخاروں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔
چوتھے نمبر پر یہ عرض ہے کہ مجھے محترم ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب کے اس ارشاد سے ایک حد تک اتفاق ہے کہ جب جمہوری اصولوں کے مطابق ایک مسلمان ملک کے مسلمان باشندوں کو اپنے مذہبی جذبات کے تحفظ کے لیے قانون بنانے کا حق حاصل ہے اور مذہبی حقوق کی خلاف ورزی کو جرم قرار دے کر اس کے سدباب کے لیے ان کا، سزاے موت مقرر کرنا ہر لحاظ سے جمہوری اصولوں کے مطابق ہے اور اس سزا کی شرعی بنیادیں بھی موجود ہیں اور حالات میں کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں آئی جو خود کسی ترمیم کا تقاضا کرتی ہو اور نہ ملک کے مذہبی وابستگی رکھنے والوں کی طرف سے کسی ترمیم کا مطالبہ ہوا ہے تو پھر الگ تحقیق لانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ملک کے جمہور مسلمانوں کو اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حسب حال قانون بنا چکے ہیں اور اس پر وہ مطمئن بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کے اس ارشاد کی فی الجملہ تائید کرتے ہوئے گزار ش ہے کہ میرے نزدیک اس مسئلے پر غور وخوض اور بحث کا اصل دائرہ یہی ہے کیونکہ یہ مسئلہ حق وباطل کا نہیں، بلکہ ترجیحات کا ہے او رشرعی دلائل کے تقابل کا نہیں، بلکہ حکمت عملی کا ہے، کیونکہ فقہاے کرام دونوں طرف موجود ہیں اور دلائل بھی دونوں کے پاس وافر ہیں۔ اصل غور طلب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تحفظ ناموس رسالت کی معروضی کشمکش اور مصلحت عامہ کی صورت حال کیا ہے؟ اس لیے اس بات پر بحث کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کی موجودہ صورت حال، آج کے عالمی تناظر میں حق وباطل کے عالمی معرکہ، تحفظ ناموس رسالت کے ناگزیر تقاضوں اور مغرب کی فکری وثقافتی یلغار کا راستہ روکنے کے لیے آج کے حالات میں کون سا موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟
دونوں میں سے جو موقف بھی آپ اختیار کریں گے، وہ شرعی موقف ہی ہوگا کیونکہ فقہاے کرام کے علمی وفقہی اختلافات میں حسن وکمال کا ایک خوب صورت پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضوں اور حالات کی ضروریات کے مطابق آپ کے پاس گنجائش موجود رہتی ہے کہ آپ مصلحت عامہ اور ملی مفاد کی خاطر ان میں سے کوئی موقف بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہی بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی کے اختیار کردہ موقف کو باطل ثابت کرنے کی بے محل بحثوں میں الجھے رہنے کی بجائے اپنی علمی صلاحیتیں اور توانائیاں یہ واضح کرنے پر صرف کریں کہ آج جس انداز میں مغرب کی ثقافتی یلغار ہماری دینی اقدار اور ملی روایات کو پامال کرنے میں مصروف ہے، توہین رسالت کا مسئلہ نارمل صورت حال میں رہنے کی بجائے مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی عالمی مہم کی صورت اختیار کر گیا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مسلمانوں کی بے لچک جذباتی وابستگی کو جس شرم ناک طریقے سے چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کو سخت سے سخت کیا جائے اور اس معاملہ میں کوئی لچک روا نہ رکھی جائے، جبکہ بہت سے فقہا کے ہاں حکومت وقت کو سیاستاً حد سے بھی زیادہ سخت اور سنگین سزا مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سادہ اور واضح استدلال کے ہوتے ہوئے توہین رسالت پر سزاے موت کے حوالے سے غیر ضروری فقہی اور فنی مباحث میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے؟
توہین رسالت کی سزا: ایک اجتہادی و اختلافی مسئلہ
مولانا حافظ صلاح الدین یوسف
(۱۹۸۷ء تا ۱۹۹۰ء میں وفاقی شرعی عدالت میں توہین رسالت کی سزا پر بحث کے دوران میں عدالت کے فاضل مشیر جناب مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے عدالت کے سامنے جو بیان دیا، اس کا ایک حصہ محمد اسماعیل قریشی ایڈووکیٹ کی کتاب ’’ناموس رسول اور قانون توہین رسالت‘‘ کے شکریے کے ساتھ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ مدیر)
جہاں تک اس مسئلے میں مذاہب کے اختلاف کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں عرض ہے کہ جمہور کا مسلک تو وہی ہے جس کا اثبات ابن تیمیہ نے ’’الصارم المسلول‘‘ میں کیا ہے، تاہم اس میں کچھ اختلاف بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ راقم نے بھی اپنے مقالے میں اول الذکر نقطہ نظر کو زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن کل کی بحث سن کر احساس ہوا کہ علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ اسے بھی بیان کیا جائے کیونکہ اس دوسرے نقطہ نظر کا تقریباً انکار کر دیا گیا ہے۔
یہ اختلاف فقہاے احناف کا ہے جن کا مذہب یہ ہے کہ سب رسول کا مرتکب اگر مسلمان ہے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا اور اگر ذمی ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقض عہد نہیں ہوگا۔ (اس کے لیے ملاحظہ ہو ہدایہ، کتاب السیر، باب الجزیہ۔ فتح القدیر لابن الہمام، باب مذکور۔ الصارم المسلول ص ۳۰۲-۳۱۳۔ احکام اہل الذمۃ لابن القیم، ج ۲، ص ۸۱۰۔ المحلیٰ، آخری جلد، مسئلہ ۱۳۱۲، باب حکم من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح الباری، کتاب استتابۃ المرتدین، باب ۴، ص ۳۰۸، مطبوعہ مصطفی بابی الحلبی، ۱۹۵۹ء۔ عبارت فتح الباری: ان کان ذمیا عزر وان کان مسلما فہی ردتہ۔ نیل الاوطار ج ۷، آخری باب، طبع منیریہ مصر)
صحیح بخاری سے حنفی مذہب کی تائید
دلچسپ بات یہ ہے کہ حنفی مذہب میں ذمی کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا اثبات ہدایہ میں علامہ ابن الہمام نے صحیح بخاری کی ان روایات سے کیا ہے جن میں آتا ہے کہ یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک کہنے کی بجائے السام علیک کہتے اور انھی احادیث [سے] امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان یا ذمی نے سب رسول کا ارتکاب صراحتاً نہیں بلکہ تعریضاً کیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس باب سے امام بخاری اور فقہاے احناف نے یہ استدلال کیا ہے کہ سب رسول اگر صراحتاً نہیں، تعریضاً ہے تو اس کا مرتکب واجب القتل نہیں ہے۔ یہ مسلک دلائل کی رو سے کیسا ہے؟ اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا انکار علمی دیانت کے منافی ہے۔
جب اس مسئلے میں اختلاف ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو اتفاقی مسئلہ کیوں لکھا ہے، جیسا کہ امام شوکانی کے حوالے سے بھی گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ جب زیادہ اہمیت کا حامل ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اتفاقی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اختلافی نقطہ نظر کو بالکل نظر انداز کر کے اتفاق واجماع کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے اور جزوی اختلافات کا ذکر نہیں کیا جاتا، جیساکہ متعدد مثالیں اس کی کتب فقہ سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور بعض دفعہ کسی فعل کی شناعت وقباحت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناعت وقباحت تو محتاج بیان ہی نہیں۔ اسی کیفیت کو نمایاں کرنے کے لیے اختلاف کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔
علاوہ ازیں جن علما نے یہ لکھا ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے، اگر اس کو محمول کر لیا جائے اس شخص پر جو کنایتاً نہیں بلکہ سب صریح کا ارتکاب کرتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اس کی نیت بالکل واضح ہے، اس لیے ایسے شخص کو من غیر استتابۃ قتل کر دیا جائے اور اس کے برعکس صورتوں میں توبہ کا موقع دیا جائے، یہ تطبیق کی ایسی صورت ہے کہ جس سے متعارض دلائل میں توافق وتطابق ہو جاتا ہے، کیونکہ راقم اب تک کی پوری بحث کی سماعت میں شریک رہا ہے اور وہ دیکھتا آ رہا ہے کہ متعارض دلائل کی رو سے فاضل عدالت کے ذہن میں ایک اشکال چلا آ رہا ہے جسے پورے زور بیان کے باوجود دور نہیں کیا جا سکا ہے اور وہ اشکال یہی ہے کہ بعض آیات وواقعات حدیث سے توبہ کا موقع دینے کا جواز نکلتا ہے اور بعض سے ا س کے برعکس ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان احادیث کو جن میں من غیر استتابۃ قتل کا ذکر ہے، سب صریح پر یا بار بار اس کا اعادہ کرنے والے پر محمول کر لیا جائے اور جن احادیث میں تعریضاً سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کا حکم نہیں دیا گیا، وہاں دیگر دلائل شرعیہ کے اقتضا کے مطابق قصد ونیت کو بھی دیکھا جائے کہ ’انما الاعمال بالنیات‘ سے ٹکراؤ نہ رہے اور صفائی کا بھی پورا موقع دیا جائے اور محض واہمے اور مفروضے پر سزا سے اجتناب کیا جائے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ادرء وا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیلہ فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبۃ (عن عائشۃ، الجامع الصغیر للسیوطی مع شرح فتاویٰ، ج ۱، ص ۲۱، طبع مصر، ۱۹۵۴ء، صححہ الحافظ السیوطی)
پاکستان کا قانون توہین رسالت اور فقہ حنفی
مولانا مفتی محمد زاہد
توہینِ رسالت کے قانون کو ختم یا اس میں تبدیلی کرنے کی جو کوشش نظر آرہی تھی اور جس کے پیچھے ایک خاص لابی بھی موجود تھی جو ہمیشہ پاکستانی عوام کے احساسات وجذبات کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے، یہ کوشش تو دینی جماعتوں کے باہمی اتحاد اور عوام کو متحرک کرنے کی صلاحیت دکھانے سے دم توڑ گئی ہے۔ اس پر یقیناًیہ جماعتیں اور عوام تبریک کے مستحق ہیں۔ اس مسئلے پر گرما گرمی کے دوران میں نے ایک نجی مجلس میں یہ بات عرض کی کہ موجودہ ماحول سے قطع نظر تعزیراتِ پاکستان کی دفعہ۱۹۵ سی کے متعدد پہلو علمی وفقہی لحاظ سے غور کے متقاضی ہیں، نارمل حالات میں علما کو ان پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس پر ایک طالب علم نے سوال کیا کہ کیا نارمل حالات میں علما کو غور کی فرصت ملے گی؟ یہ سوال میرے ذہن کے ساتھ چپک کر رہ گیا ہے اور ابھی تک میرے دماغ میں گدگدی کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس مسئلے پر عوامی اجتماعات میں جو طرزِ گفتگو اختیار کیا گیا یا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے یہ تاثر عام ہو گیا ہے کہ یہ قانون ہماری قانون کی کتاب پر جس انداز سے موجود ہے، اسی طرح سے یہ اجماعی اور قطعی ہے جس میں کسی پہلو میں نہ تو فقہا کے درمیاں کوئی اختلاف موجود ہے اور نہ ہی کسی اختلاف کی گنجائش۔ عامۃ الناس سے لے کر اچھے خاصے پڑھے لکھوں تک بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، جبکہ کسی شرعی مسئلے کی درست حیثیت واضح کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہے ۔ اس لیے خیال ہوا کہ فقہی عبارات اور اصطلاحات سے بوجھل کیے بغیر عام قاری کے لیے کم از کم فقہ حنفی کی پوزیشن اس مسئلے پر واضح کردی جائے جس پر یہاں کے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت عمل پیرا ہے۔
اگر یہ سوال کیا جائے کہ فقہ حنفی میں کیا شاتمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا موت ہے اور یہی متعین سزا ہے تو جواب اثبات میں ہوگا ۔ لیکن دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس سزا کی فقہ حنفی میں نوعیت کیا ہے؟ یہ سوال بھی کم اہم نہیں ہے ، اس لیے کہ یہ سزا کہاں لاگو ہوگی اور کہاں نہیں، اس کا فیصلہ اسی سوال کے جواب سے ہوگا۔ فقہِ حنفی کے ایک طالب علم کے لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ متعین سزا در حقیقت ارتداد کی سزاہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی کتب میں اس سزا کا تذکرہ عموماً کتاب الحدود کی بجائے کتاب الجہاد کے باب المرتد میں ملتاہے۔ فقہ حنفی سے واقفیت رکھنے والے کے لیے یہ بات حوالہ جات کی محتاج نہیں ۔ سزا کی نوعیت کے اس تعین کے بعد اس پر چند اثرات خود بخود مرتب ہو جاتے ہیں اور ان اثرات کی تصریح بھی فقہ حنفی کی کتب میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہ سطور ایک عام قاری کو مد نظر رکھ کرلکھی جارہی ہیں، اس لیے یہاں عبارات پیش کرنے سے گریز کیا جارہاہے۔ ( اہلِ علم کے لیے الشریعہ گوجرانوالہ میں مارچ ۲۰۱۱ء میں شائع ہونے والے مولانا مفتی محمد عیسیٰ صاحب گورمانی اور جناب پروفیسر مشتاق احمد صاحب کے مضامین کا مطالعہ مفید ہوگا)۔
(۱) جب یہ طے ہوگیا کہ یہ سزا ارتداد کے زمرے میں آتی ہے تو یہ بات بھی خود بخود طے ہوجاتی ہے کہ اس سزا کا اطلاق اسی شخص پر ہوگا جو پہلے سے مسلمان ہو۔ جو پہلے سے ہی غیر مسلم ہو، وہ ظاہر ہے کہ مرتد نہیں کہلا سکتا، اس متعین سزا کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ غیر مسلم اگر ایسا فعل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا جواب ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔
(۲) چونکہ یہ سزا ارتداد کے طور پر دی جارہی ہے، اس لیے جس بات پر یہ سزا دی جائے، اس میں ان تمام احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا جو فقہا کے نزدیک کسی شخص کو کافر اور مرتد قرار دینے کے لیے ضروری ہیں۔
(۳) مرتد کے بارے میں فقہ حنفی کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرلے تو اس کی توبہ نہ صرف یہ کہ قبول کی جاتی ہے بلکہ قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے توبہ کی تلقین کرنے کا انتظام کرے اور اسے اس کا موقع دے۔
ہمارے ہاں جلسے جلوسوں میں جوشِ خطابت میں یہ بات کثرت سے کہی گئی ہے کہ اس جرم کی کوئی توبہ نہیں اور کسی انسان کو توبہ کی بنیاد پر یہ سزا معاف کرنے کا اختیار نہیں اور یہ کہ یہ بات امت میں ہمیشہ سے مسلمہ چلی آرہی ہے، جبکہ توبہ قبول نہ کرنے کا نقطۂ نظر بعض فقہا نے اختیار ضرور کیا ہے، لیکن فقہ حنفی کا یہ نقطۂ نظر ہر گز نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی ؒ کی شخصیت سے فقہ حنفی کا کوئی بھی طالب علم ناواقف نہیں ہوسکتا ۔ ان کی کتابوں سے حنفی اہل افتا کے ہاں سب سے زیادہ استفادہ کیا جاتاہے۔ انہوں نے اپنی متعدد کتب میں مسئلے کے اس پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ۔ اہلِ علم ان کی کتاب رد المحتار کے باب أحکام المرتدین اور توہین رسالت کے مسئلے پر ان کے مشہور رسالے ’’ تنبیہ الولاۃ والحکام‘‘ ( جو مجموعہ رسائل ابن عابدین میں شامل ہے) کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔
نویں صدی ہجری کے ایک حنفی عالم البزازیؒ (وفات: ۸۲۷ھ) نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو نے کے بعد سچے دل سے توبہ کرلیتا ہے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کرتاہے، تب بھی اس کی سزا معاف نہیں ہو گی۔ بزازی کے بعد آنے والے بعض حضرات نے بھی ان کی یہ بات اسی طرح سے نقل کر دی، لیکن علامہ شامی ؒ نے البزازی کی اس بات پر شدید رد کیاہے اور یہ بتایا ہے کہ ان سے پہلے فقہ حنفی کا نقطۂ نظر، خواہ وہ کسی حنفی عالم نے بیان کیا ہو یا غیر حنفی نے، سب نے یہی بتایا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق شاتم رسول کی توبہ قابل قبول ہے۔ فقہ شافعی کا نقطۂ نظر بھی حنفیہ کے قریب قریب ہے۔ فقہ مالکی اور فقہ حنبلی میں بھی ایک ایک قول یہی ملتاہے۔ اہل علم مسئلے کی علمی تفصیل تو مذکورہ حوالوں میں دیکھ سکتے ہیں، البتہ یہاں امام ابوحنیفہؒ کے براہِ راست شاگرد امام ابو یوسف ؒ کی عبارت کا ترجمہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتاہے۔ وہ فرماتے ہیں:
’’جو مسلمان مرد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے ، آپ کی تکذیب کرے ، آپ کی عیب جوئی کرے یا آپ کی تنقیص کرے تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اس کی بیوی اس سے جدا ہوجائے گی ۔ اگر وہ توبہ کرلے تو ٹھیک وگرنہ اسے قتل کردیا جائے گا۔ یہی حکم عورت کاہے، تاہم امام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک عورت کو (توبہ نہ کرنے کے باوجود بھی ) قتل نہیں کیا جائے گا۔‘‘ ( کتاب الخراج ص۱۸۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)
یاد رہے کہ کتاب الخراج در حقیقت امام ابو یوسف کا خلیفہ ہاورن الرشید کے نام خط ہے، اس لیے اس میں جو کچھ وہ تحریر فرمارہے ہیں، اس کی مخاطب ریاست ہے۔
بہر حال شاتمِ رسول کی توبہ قبول نہ ہونے کا قول بزازیؒ سے پہلے حنفیہ میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ گویا نویں صدی ہجری تک فقہ حنفی میں اس بات کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ پھر بزازی ؒ نے جو کچھ لکھا ہے، اس کے بارے میں علامہ شامی نے تفصیل سے ثابت فرمایا ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ ان کی رائے نہیں ہے بلکہ انہیں بعض عبارات کے سمجھنے میں شدید غلطی ہوگئی ہے۔ تاہم فقہ حنفی ہی کی معروف کتاب ’’الدر المختار‘‘ ( ج۴ص ۲۳۶) میں یہ ذکر کیا ہے کہ ۹۴۴ھ میں یہ امرِ سلطانی جاری ہوا تھا کہ اگر مجرم کی توبہ سچی معلوم ہو، پھر تو حنفیہ کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے توبہ قبول کرلی جائے اور سزاے موت کی بجائے قید وغیرہ تعزیری سزا پر اکتفا کیا جائے اور اگر ایسا شخص ہو جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو ، توبہ محض بہانہ ہو (جس کا پتا اس جرم کے تکرار سے بھی چل سکتاہے) تو فقہ حنفی کے علاوہ بعض دیگر فقہا کے قول پر عمل کرتے ہوئے اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ۱۹۹۰ء میں اس مسئلے پر وفاقی شرعی عدالت کے معروف فیصلے، جس کی روشنی ہی میں پارلیمنٹ نے اس جرم پر عمرقید کی سزا کو حذف کرکے صرف سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ عدالت میں پیش ہونے والے متعدد اہل علم نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ اس قانون میں توبہ کا موقع ملنا چاہیے۔ ان علما میں دیوبندی مکتبِ فکر سے دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث مولانا سبحان محمودؒ ، بریلوی مکتب فکر کے معروف عالم مفتی غلام سرور قادریؒ اور معروف اہلِ حدیث عالم حافظ صلاح الدین یوسف قابلِ ذکر ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شرعی عدالت کے فیصلے میں جو بحث کی گئی ہے، اس بحث کی پوری جھلک کورٹ آرڈر اور اس کی روشنی میں ہونے والی قانون سازی میں نظر نہیں آتی۔ بہتر ہوتا کہ اس وقت یہ مسئلہ اپیل کے لیے سپریم کے شریعت بنچ میں چلاجاتا جہاں اس وقت مفتی محمد تقی عثمانی اور پیر کرم شاہ ؒ جیسے جید علما موجود تھے۔ اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے اپیل کی بھی گئی تھی، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہ اپیل واپس لینے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اس جرم کی سزا اگر موت سے بڑھ کر کوئی ہوتی تووہ تجویز کی جاتی۔ نواز شریف صاحب کا جذبہ قابلِ قدر، لیکن بہر حال وہ باقاعدہ عالم دین نہیں ہیں۔ جناب اسماعیل قریشی ایڈووکیٹ صاحب نے ایک کتابچے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس وقت وزیرِ اعظم کو پیغام بھیجا تھا کہ یہ اپیل واپس لی جائے ’’وگرنہ مسلمانوں کے جذبات اس حکومت کے خلاف بھی مشتعل ہو جائیں گے‘‘۔ اسماعیل قریشی صاحب ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں، خاص طور پر ان کا جذبہ عشق رسول سب کے لیے مشعلِ راہ ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ کسی شرعی مسئلے کو ماہرینِ شریعت پر مشتمل آئینی فورم پر اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں مزید غور کرلیا جائے تو اس میں جذبات مشتعل ہونے والی کون سی بات تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ اس مسئلے میں شروع ہی سے صرف ایک نقطہ نظر کو جو کہ یہاں کی اکثریتی فقہ سے بھی مطابقت نہیں رکھتا، ایمان اور عقیدے کا درجہ دے دیاگیا تھا۔ یاد رہے کہ مذکورہ فیصلہ صادر کرنے والے وفاقی شرعی عدالت کے بنچ میں کوئی باقاعدہ عالم دین شامل نہیں تھے ، جبکہ سپریم کورٹ کے شریعت پنج میں مذکورہ دو جید عالم موجود تھے۔
(۴) چوتھا نتیجہ سزا ئے موت کی مذکورہ فقہی نوعیت کا یہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ ؒ کے مذہب کے مطابق اس قانون کے تحت عورت کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، جیسا کہ امام ابو یوسف کی عبارت میں گزرا ۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام ابویوسفؒ کی مذکورہ تصریح عمومی طور پر مرتد ہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ خاص طور پر شاتمہ رسول کے بارے میں ہے۔
اب تک کی گفتگوکا حاصل یہ ہے کہ فقہ حنفی کی رو سے شاتمِ رسول کے سزائے موت متعین ہے بشرطیکہ جس سے جرم سرزد ہواہے، وہ مسلمان مرد ہو اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور جرم کی نوعیت ایسی ہو کہ اسے بلاشک وشبہ ارتداد میں داخل کیا جاسکے۔ اگر کسی مجرم میں ان میں کوئی شرط مفقود ہو، مثلاً توہین کرنے والا غیر مسلم ہو یا ملزمہ عورت ہو توکیا اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے ؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوسکتا۔ ایک مسلمان معاشرے اور ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک انتہائی سنگین برائی ہے اور اسلامی ریاست کے فرائض میں برائیوں کی روک تھام بھی شامل ہے اور برائیوں کی روک تھام کے لیے سزا پر مشتمل قوانین بھی ناگزیر ہوتے ہیں۔ مذکورہ شرائط مفقود ہونے کی صورت میں شرعی طور پر کوئی متعین سزا تو موجود نہیں ہے، ایسے موقع پر تعزیری سزا سے کام لیا جاتاہے۔ تعزیری سزا سے مراد وہ سزا ہے جو شریعت نے از خود متعین نہیں کی ہوتی، اس کے بارے ریاست یا ریاستی اداروں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جرم اور مجرم کی نوعیت دیکھ کر اور حالات اور مصالح کو سامنے رکھ کر جو سزا مناسب سمجھیں، تجویز کرسکتے ہیں۔ناگزیر حالات میں بطور تعزیر سزائے موت بھی دی جاسکتی ہے، بلکہ جہاں جرم کی نوعیت شدید ہو، وہاں سزائے موت ملنی چاہیے۔ مثلاً وہ علانیہ طور پر بار بار اس جرم کا ارتکاب کرتاہے یا جرم کے انداز میں ڈھٹائی اور سرکشی واضح طور پر نظر آرہی ہے۔
اس پر بحث ہوسکتی ہے کہ موجودہ حالات میں فقہ حنفی کے نقطۂ نظر کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہوگا یا کسی اور رائے کو۔ موجودہ قانون فقہ حنفی کی بجائے بنیادی طور پر ابن تیمیہؒ کی رائے کی نمائندگی کرتاہے۔ وہ بھی ایک قابلِ احترام رائے ہے، لیکن جس مسئلے میں فقہ حنفی کا اختلاف موجود ہو، اسے مسلمہ اور اجماعی مسئلے کے طور پر پیش کرنا بہر حال ایک دینی مسئلے کی غلط تصویر دکھاناہے۔ تاہم یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں توہین رسالت جیسا سنگین جرم کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے ۔ اس کی روک تھام کے لیے قانون تو ضرور ہو، تاہم اس قانون کی تفصیلات پر دلائل شرعیہ کی روشنی میں غور ہوسکتا ہے ۔اہلِ علم سے یہ درخواست ہے کہ مسئلے کے تمام پہلوؤں کو اور ملک کی معروضی صورتِ حال کو سامنے رکھ کر سنجیدہ غور کا سلسلہ شروع کریں اور بجائے اس کے کہ کوئی موقع دیکھ کر حکومت کوئی لسٹم پسٹم ترمیم لے آئے اور دینی حلقوں کے ساتھ اسی طرح کا ہاتھ ہوجائے جیسا ۲۰۰۷ء میں حدود کے مسئلے پر ہوا تھا، علما کے لیے مناسب ہوگا کہ مختلف طبقات کے جائز تحفظات کو سامنے رکھ کر از خود قرآن وسنت کی روشنی میں کوئی قانونی پیکیج پیش کر دیں۔
جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، یہاں دلائل کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے ۔ تاہم اختصار کے ساتھ اتنا عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں عہدِ رسالت کے جن واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کا اسلامی ریاست کا شہری ہونا ہی ثابت نہیں ہے۔ بعض تو محارب ( بر سرِ پیکار ) تھے۔ بعض کے اس جرم کے علاوہ اور بھی کئی جرائم تھے اور یہ بات تو اکثر وبیشتر واقعات میں ہے کہ ان سے یہ جرم ایک آدھ مرتبہ صادر نہیں ہوا تھا، بلکہ بار بار اور عادت کے طور پر انہوں نے یہ وطیرہ اپنایا ہوا تھا۔ اس جرم پر سیاسۃً یا تعزیراً سزائے موت کے سلسلے میں متعدد فقہاء حنفیہ نے اسی صورتِ حال یعنی عادت اور تکرار کا ذکر کیاہے۔ اس سلسلے میں صرف ابوداود کی ایک روایت کی مثال دینا مناسب ہوگا جس کا ہمارے ہاں عام تقریروں میں بکثرت حوالہ دیا گیاہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی باندی کو اس وجہ سے قتل کردیا تھا کہ وہ آنحضرتصلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہوئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ لیکن اسی واقعے میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ باندی بار بار ایساکررہی تھی کہ اور اس صحابی نے اسے کئی بار سمجھا بجھایا بھی، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئی ۔ اس سے یہ بات بھی نکل رہی ہے کہ اس مسئلے میں سمجھانے بجھانے کا بھی کوئی خانہ موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ اتنی مرتبہ سمجھانے بجھانے میں کیوں لگے رہے، تمہیں تو پہلی مرتبہ اسے سزائے قتل دلوانے کی فکر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس طرح کی بات ایک دفعہ منہ سے نکلنے کے بعد سزائے موت کے علاوہ کوئی پہلو زیر غور آہی نہیں سکتا۔
حقیقت یہ ہے کہ ہم عہد رسالت کے توہین رسالت کے واقعات کو جب اس انداز پیش کرتے ہیں جس سے یہ تاثر ابھرتاہے کہ ابن خطل جیسے کچھ لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کستاخی کے چند لفظ نکلے تو محض اتنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ خواہ وہ کتنی معافیاں مانگ لے، اس کے لیے آپ نے معافی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی اور غلافِ کعبہ پکڑے ہوئے ہوں، تب بھی انہیں قتل کرنے کا حکم دیا( کیونکہ ابن خطل جیسے لوگوں کے دیگر جرائم اور شرانگیزیوں کا ہم تذکرہ کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہماری خطابتوں کے سیاق وسباق سے عام سیدھا سادہ آدمی یہی تصور کرتا ہے کہ یہ لوگ آسیہ مسیح جتنے ہی مجرم ہوں گے۔) جب اس انداز سے ہم ان واقعات کو پیش کررہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی درست تصویر کشی کررہے ہیں اور کیا ہم آپ کی سیرتِ مبارکہ کی خدمت کررہے ہیں؟ یہ سب کچھ جذبۂ محبت میں اور نیک نیتی سے سہی، لیکن غیرشعوری طور پر اپنے نتائج کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغرب کے ملعون کارٹون سازوں کے مقاصدکی تو اس سے تائید نہیں ہو رہی اور ہم کہیں یہ تأثر تو پیدا نہیں کر رہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ألف مرۃ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ایک دفعہ بھی جب کوئی ان کے خلاف بات کہہ دیتا تھا تو اسے کسی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے طرزِ عمل کے بارے میں ممکن ہے، میرا یہ احساس درست نہ ہو، تاہم غور کے لیے یہ سوال اہل علم وفکر کی خدمت میں پیش کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا۔ اگر کوئی صاحب اس نا کارہ کی غلطی پر تنبیہ فرمائیں گے تو خوشی ہوگی۔
میری علمی و مطالعاتی زندگی
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(جناب عرفان احمد، مدیر ماہنامہ ’’نواے کسان‘‘ لاہور کے مرتب کردہ سوال نامہ کے جوابات۔)
۱۔ کچھ ذاتی حالات زندگی کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔
ہمارا تعلق ضلع مانسہرہ، ہزارہ میںآباد سواتی خاندان سے ہے جس کے آبا و اجداد کسی زمانے میں سوات سے نقل مکانی کر کے ہزارہ میں آباد ہوگئے تھے۔ ہمارے دادا نور احمد خان مرحوم شنکیاری سے آگے کڑمنگ بالا کے قریب چیڑاں ڈھکی میں رہتے تھے اور زمینداری کرتے تھے۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر ؒ اور عم مکرم حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتیؒ کی نو عمری میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوگیا۔ والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ دونوں حضرات دینی تعلیم کی طرف آگئے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ کے مدرسہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر پنجاب کے مختلف مدارس، بالخصوص مدرسہ انوار العلوم، مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں درس نظامی کا بڑا حصہ پڑھا۔ ۱۹۴۱ ۔۱۹۴۲ء میں دار العلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر ؒ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ؒ کے ممتاز تلامذہ میں سے تھے۔ وہ مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے شیخ الحدیث رہے ہیں اور کم و بیش ساٹھ سال تک تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں۔ دیوبندی مسلک کے علمی ترجمان سمجھے جاتے تھے اور کم و بیش پچاس کے لگ بھگ کتابوں کے مصنف تھے۔
میری ولادت ۱۹۴۸ء میں ۲۸؍اکتوبر کو ہوئی۔ میری والدہ محترمہ کا تعلق راجپوت خاندان سے تھا اور ہمارے نانا مرحوم مولوی محمد اکبر صاحب گوجرانوالہ میں ریلوے اسٹیشن کے قریب تالاب دیوی والا، رام بستی کی ایک مسجد کے امام تھے۔ ان کا تعلق راجپوت جنجوعہ برادری سے بتایا جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید گکھڑ کے مدرسہ تجوید القرآن میں مختلف اساتذہ سے حفظ کیا جس میں سب سے آخری اور بڑے استاد قاری محمد انور صاحب ہیں جو کہ آج کل مدینہ منورہ میں تحفیظ القرآن کے استاد ہیں۔ ۲۰ ؍اکتوبر ۱۹۶۰ء کو میرا حفظ مکمل ہونے پر گکھڑ کی جامع مسجد میں جو تقریب ہوئی، اس میں حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی، حضرت مولانا قاری فضل کریم اور حضرت مولانا قاری محمد حسن شاہ صاحب نے شرکت فرمائی تھی اور میں نے آخری سبق ان بزرگوں کو سنایا تھا۔ درس نظامی کے بڑے حصہ کی تعلیم میں نے مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں حاصل کی اور میرے اساتذہ میں حضرت والد محترم اور حضرت عم مکرم کے علاوہ حضرت مولانا عبدالقیوم ہزاروی مدظلہ، حضرت مولانا قاضی محمد اسلم صاحب، حضرت مولانا قاضی عزیز اللہ صاحب اور حضرت مولانا جمال احمد بنوی مظاہری بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں مدرسہ نصرۃ العلوم سے میں نے فراغت حاصل کی۔
دوران زمانہ طالب علمی مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحبؒ کی معاونت کے لیے بطور نائب خطیب میرا تقرر ہو چکا تھا، جبکہ اس سے قبل کم و بیش دو سال تک گتہ مل راہوالی کی کالونی کی مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتا رہا تھا۔ ۱۹۸۲ء میں مولانا مفتی عبد الواحدؒ کی وفات کے بعد مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ کے مستقل خطیب کی حیثیت سے میں نے ذمہ داری سنبھال لی تھی جوکہ بحمد اللہ تعالیٰ اب تک حسب استطاعت نباہ رہا ہوں۔ مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ کے مدرسہ انوار العلوم میں ہی ۱۹۷۰ء سے ۱۹۹۰ء تک درس نظامی کی تدریس کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں، جبکہ گزشتہ دس گیارہ سال سے مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں تدریسی خدمات میرے سپرد ہیں اور والد محترم کے بعد صدارت تدریس اور نظامت تعلیمات کی ذمہ داری بھی میرے ناتواں کندھوں پر ہے۔
صحافتی زندگی میں طالب علمی کے دوران ۱۹۶۵ء میں روزنامہ ’’وفاق‘‘ لاہور کے نامہ نگار کی حیثیت سے داخل ہوا۔ ۶۵ء کی پاک بھارت جنگ میں گکھڑ پر بھارتی فضائیہ کی بمباری کے حوالہ سے پہلا فیچر لکھا اور شہری دفاع کے رضاکار کے طور پر خدمات بھی سر انجام دیں۔اس کے بعد جمعیت علمائے اسلام کے آرگن ہفت روزہ ’’ترجمان اسلام‘‘ لاہور کے ساتھ تعلق رہا اور متعدد بار کئی برس تک ایڈیٹر کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیے۔ روزنامہ ’’پاکستان‘‘ اسلام آباد اور روزنامہ ’’اوصاف‘‘ اسلام آباد میں کئی سال مستقل کالم نگار کے طور پر وابستہ رہا اور ’’نوائے قلم‘‘ کے نام سے ہفتہ وار کالم لکھتا رہا۔ اب یہ کالم روزنامہ ’’پاکستان‘‘ لاہور میں لکھ رہا ہوں جبکہ روزنامہ ’’اسلام‘‘ میں بھی ’’نوائے حق‘‘ کے عنوان سے ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں۔ جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے ترجمان ماہنامہ ’’نصرۃ العلوم‘‘ کا اداریہ بھی کئی برسوں سے تحریر کر رہا ہوں۔
بیرون ملک ختم نبوت کانفرنسوں اور ورلڈ اسلامک فورم کی سرگرمیوں کے علاوہ دیگر تعلیمی، دعوتی اور مطالعاتی مقاصد کے لیے کئی ممالک میں جانا ہوا، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، جنوبی افریقہ، بھارت، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکی، ہانگ کانگ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور کینیا شامل ہیں۔ مدرسہ نصرۃ العلوم کی سالانہ تعطیلات کے دوران شعبان المعظم اور اس کے ساتھ رمضان المبارک کا کچھ حصہ برطانیہ اور امریکہ میں تعلیمی سرگرمیوں میں مصروفیت رہتی ہے اور متعدد دینی اداروں سے مشاورت اور معاونت کا تعلق ہے۔
سیاسی و تحریکی ذوق طالب علمی کے دور سے چلا آرہا ہے۔ جمعیت طلباء اسلام پاکستان کو منظم کرنے میں حصہ لیا۔ گکھڑ میں انجمن نوجوانان اسلام کے نام سے نوجوانوں کی تنظیم بنائی اور جمعیت علمائے اسلام میں بتدریج شہر، ضلع، صوبہ اور مرکز کی سطح پر سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے کاموقع ملا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے میرا انتخاب حضرت مولانا مفتی محمودؒ کی تجویز پر ۱۹۷۵ء میں ہوا اور پھر ان کی وفات تک ان کی معاون ٹیم کے ایک متحرک رکن کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ ۱۹۷۴ء اور ۱۹۸۴ء کی تحریک ختم نبوت میں عملی حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ۱۹۸۴ء کی تحریک ختم نبوت میں مرکزی مجلس عمل کے سیکرٹری اطلاعات کے طور پر کام کیا۔ ۱۹۷۷ء میں پاکستان قومی اتحاد قائم ہوا تو اس کی دستور ساز اور منشور ساز کمیٹیوں اور پارلیمانی بورڈ میں جمعیت کی نمائندگی کی۔ پنجاب کا قومی اتحاد کا نائب صدر اور پھر سیکرٹری جنرل رہا۔ ۱۹۸۸ء میں اسلامی جمہوری اتحاد قائم ہوا تو اس میں بھی دستور ساز اور منشور ساز کمیٹیوں میں جمعیت علماء اسلام (درخواستی گروپ) کی نمائندگی کی اور صوبائی نائب صدر رہا۔ ۱۹۹۰ ء میں جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے منصب سے مستعفی ہو کر عملی سیاست سے کنارہ کش ہوگیا۔
تحریک ختم نبوت ، تحریک نظام مصطفی، گوجرانوالہ میں مسجد نور کو محکمہ اوقاف سے واگزار کرانے کی تحریک اور دیگر متعدد تحریکات میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بھٹو دور میں کئی بار جیل یاترا کی۔ مسجد نور کی تحریک میں کم و بیش چار ماہ اور تحریک نظام مصطفی میں ایک ماہ جیل کاٹی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد بار تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے جیل جانے کا موقع ملا۔
سیاسی طور پر جمعیت علماء اسلام پاکستان سے وابستہ رہا۔ کم و بیش پچیس برس تک صوبائی اور مرکزی سطح پر مختلف عہدوں پر متحرک کردار ادا کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمودؒ کے رفیق کار اور اسسٹنٹ کے طور پر سالہا سال خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا۔ اب ایک عام کارکن کے طور پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شریک ہوں جبکہ انتخابی سیاسی سے ہٹ کر فکری اور علمی حوالہ سے اسلامائزیشن کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کر رہا ہوں جس کے امیر مولانا فداء الرحمن درخواستی آف کراچی ہیں۔
گزشتہ عشرہ کے اوائل میں لندن میں مولانا محمد عیسیٰ منصوری اور مفتی برکت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر ایک فکری اور علمی فورم ’’ورلڈ اسلامک فورم‘‘ کے نام سے قائم کیا جو کہ علمی اور فکری میدان میں عصر حاضر کے تقاضوں کا احساس اجاگر کرنے میں مصروف ہے اور اس کی سرگرمیوں کا دائرہ برطانیہ، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے دیگر شرکا و معاونین میں ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم ، ڈاکٹر سلمان ندوی الحسینی اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمیؒ شامل رہے ہیں۔
۱۹۸۹ء میں الشریعہ اکادمی قائم کی جس کا مقصد دعوت اسلام اور دینی تعلیم کے حوالے سے عصری تقاضوں کو اجاگر کرنا اور ان کی طرف دینی حلقوں کو توجہ دلانا تھا۔ یہاں ہم دینی تعلیم کے ساتھ عصری تقاضوں کے امتزاج کا تجربہ کر رہے ہیں اور اس ضمن میں مختلف کورسز ہر سال ہوتے ہیں۔ اکتوبر ۱۹۸۹ء سے ماہنامہ ’الشریعہ‘ باقاعدگی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے جو اسلام اور ملت اسلامیہ کو درپیش معروضی مسائل کے حوالے سے اپنی بساط کے مطابق خدمت کر رہا ہے اور علمی حلقوں میں بحمد اللہ تعالیٰ اسے توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الشریعہ اکادمی کی باقاعدہ بلڈنگ ہاشمی کالونی، کنگنی والا، گوجرانوالہ میں تعمیر کی گئی ہے جس میں مسجد اور لائبریری بھی شامل ہے اور اس میں سال بھر فکری اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رہتی ہے۔ دینی مدارس اور اسکول وکالج کے طلبہ کے لیے سال میں انگریزی بول چال، عربی بول چال، کمپیوٹر ٹریننگ وغیرہ کے مختصر دورانیے کے مختلف کورسز ہوتے ہیں اور علمی وفکری عنوانات پر محاضرات، سیمینارز اور ورک شاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
۲۔ آپ کے اندر ذوق مطالعہ کب نمایاں طور پر پیدا ہوا؟ آغاز کیسے ہوا؟ اس کی نشوونما کس طرح ہوئی؟ خاندانی نظام تربیت کا اثر کہاں تک ہوا؟
کتاب کے ساتھ میرا تعارف بحمد اللہ تعالیٰ بہت پرانا ہے اور اس دور سے ہے جبکہ میں کتاب کے مفہوم اور مقصد تک سے آشنا نہیں تھا۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا گھر میں زیادہ تر وقت لکھنے پڑھنے میں گزرتا تھا اور ان کے اردگرد الماریوں میں کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں۔ اس لیے کتاب کے چہرہ سے شناسائی تو تب سے ہے جب میں نے اردگرد کی چیزوں کو دیکھنا اور ان میں الگ الگ فرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد کتاب سے دوسرے مرحلے کا تعارف اس وقت ہوا جب میں نے دو چار حرف پڑھ لیے اور کم از کم کتاب کا نام پڑھ سکتا تھا۔ والد صاحب ایک چارپائی پر بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اور حوالہ کے لیے کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت ہوتی تو خود اٹھ کر متعلقہ الماری سے وہ کتاب لے لیا کرتے تھے، مگر جب میں اور میری بڑی ہمشیرہ الفاظ کی شناخت کے قابل ہوگئے تو پھر اس کام میں ہماری شرکت بھی ہوگئی، اس حد تک کہ ہم میں سے کوئی موجود ہوتا تو والد صاحب کو کتاب کے لیے خود الماری تک نہیں جانا پڑتا تھا بلکہ وہ ہمیں آواز دیتے کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد نکال لاؤ اور ہم میں سے کوئی یہ خدمت سر انجام دے دیتا۔ ابتدا میں والد صاحب کو ہمیں یہ بتانا پڑتا تھا کہ فلاں الماری کے فلاں خانے میں اس نام کی کتاب ہے، اس کی اتنے نمبر کی جلد نکال لاؤ۔ بعد میں کتابوں سے ہمارا تعارف گہرا ہوگیا تو وہ صرف کتاب اور جلد نمبر کا کہتے اور ہم کتاب نکال لاتے اور اس کے لیے بسا اوقات ہم دونوں بہن بھائیوں میں مقابلہ بھی ہوتا کہ کون پہلے کتاب نکال کر لاتا ہے۔ اس وقت کی جن کتابوں کے نام ابھی تک ذہن کے نقشے میں محفوظ ہیں، ان میں السنن الکبریٰ، لسان المیزان، تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، تاریخ بغداد اور نیل الاوطار بطور خاص قابل ذکر ہیں جو علمِ حدیث اور اسماءِ رجال کی کتابیں ہیں اور یہ حضرت والد صاحب کے خصوصی ذوق کے علوم ہیں۔ ان کتابوں کے نام، ٹائٹل اور جلدیں بچپن میں ہی ذہن پر نقش ہوگئی تھیں اور یہ نقش ابھی تک اس طرح تازہ ہیں جیسے آج ہی ان کتابوں کو دیکھا ہو۔
پھر ایک قدم اور آگے بڑھا اور کتابوں کو خود پڑھنے کی منزل آگئی۔ اس کے لیے میں گکھڑ کے ایک مرحوم بزرگ ماسٹر بشیر احمد صاحب کشمیری کا ممنون احسان ہوں کہ ان کی بدولت کتاب کے مطالعہ کی حدود میں قدم رکھا۔ ماسٹر بشیر احمد کشمیریؒ پرائمری سکول کے ٹیچر تھے اور حضرت والد محترم کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ان کے خاندان سے ہمارا گہرا خاندانی تعلق تھا۔ انہیں ہم چاچا جی کہا کرتے تھے اور وہ بھی ہم سے بھتیجوں جیسا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کو ہم بے جی کہتے تھے اور ان کی ہمشیرگان ہماری پھوپھیاں کہلاتی تھیں۔ انہی میں سے ایک پھوپھی اب میرے چھوٹے بھائی مولانا عبد القدوس قارن کی خوش دامن ہیں۔ والد محترم کو جب کسی جلسہ یا دوسرے کام کی وجہ سے رات گھر سے باہر رہنا پڑتا تو بے جی اس روز ہمارے ہاں رات گزارتی تھیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنایا کرتی تھیں جس کی وجہ سے ہم بہت خوش ہوتے تھے اور ہمیں ایسی رات کا انتظار رہتا تھا۔
ماسٹر بشیر احمد صاحب امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری ؒ کے شیدائی اور احرار کے سرگرم کارکن تھے۔ وہ حضرت شاہ جی ؒ کی گکھڑ تشریف آوری اور جلسہ سے خطاب کا واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے اور میرے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ میں بالکل گود کا بچہ تھا اور مجھے حضرت شاہ جی ؒ نے گود میں اٹھایا تھا، اس لیے مجھ سے اگر کوئی دوست پوچھتا ہے کہ کیا تم نے امیر شریعتؒ کی زیارت کی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے تو یا دنہیں ہے، البتہ شاہ جیؒ نے مجھے دیکھا ہے۔ ماسٹر صاحب کے ہاں ہفت روزہ خدام الدین، ترجمان اسلام، ماہنامہ تبصرہ، ہفت روزہ پیام اسلام، ہفت روزہ چٹان اور دیگر دینی جرائد آیا کرتے تھے۔ میں ان جرائد سے انہی کے ہاں متعارف ہوا اور وہیں سے رسالے پڑھنے کی عادت شروع ہوئی۔ حضرت والد صاحب کے پاس دہلی سے ماہنامہ برہان، ملتان سے ماہنامہ الصدیق، چوکیرہ (سرگودھا) سے ماہنامہ الفاروق اور فیصل آباد (تب لائل پور) سے ہفتہ روزہ پاکستانی آیا کرتے تھے جو میری نظر سے گزرا کرتے تھے۔ جامع مسجد بوہڑ والی گکھڑ کے حجرہ کی الماری میں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی جس کے انچارج ماسٹر صاحب مرحوم تھے۔ اس میں زیادہ تر احرار راہ نماؤں کی کتابیں تھیں۔ وہیں سے میں نے وہ کتابیں لیں جو میری زندگی میں مطالعہ کی سب سے پہلی کتابیں ہیں۔ چودھری افضل حق مرحوم کی کتاب ’’زندگی‘‘ اور ’’تاریخ احرار‘‘ مولانا مظہر علی اظہر کی ’’دنیا کی بساط سیاست‘‘ اور آغا شورش کاشمیری کی ’’خطبات احرار‘‘ پہلی کتابیں ہیں جن کا میں نے باقاعدہ مطالعہ کیا۔ کچھ سمجھ میں آئیں اور اکثر حصے ذہن کے اوپر سے ہی گزر گئے، لیکن بہرحال میں نے اپنی مطالعاتی بلکہ فکری زندگی کا آغاز ان کتابوں سے کیا۔
ہماری والدہ مرحومہ گوجرانوالہ سے تھیں۔ شیرانوالہ باغ کے سامنے ریلوے پھاٹک سے دوسری طرف واقع پولیس تھانے کے عقب میں رام بستی نامی محلہ کی مسجد میں ہمارے نانا مرحوم مولوی محمد اکبر صاحب امام مسجد تھے جو راجپوت جنجوعہ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑے باذوق بزرگ تھے۔ قرآن کریم معروف لہجے میں اور اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے جو اس زمانہ میں بہت کمیاب تھے۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن میں نے بہت سے معیاری علمی جرائد ان کے ہاں سے ڈاک میں باقاعدہ آتے دیکھے جن میں الفرقان، النجم، برہان، خدام الدین اور دروس قرآن جیسے رسالے بھی شامل تھے۔ وہ ان کا مطالعہ کرتے اور اہتمام سے ان کی جلدیں بنواتے تھے۔
اس کے بعد جب ۶۳ء میں مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں داخل ہوا اور مدرسہ کے دار الاقامہ میں ایک آزاد طالب علم کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کیا تو میں نے اس آزادی کا خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ گھومنا، پھرنا، جلسے سننا، لائبریری تلاش کرنا، رسالے ڈھونڈنا، کتابیں مہیا کرنا اور ان کا مطالعہ کرنا میرے روز مرہ معمولات میں شامل ہوگیا تھا۔ درسی کتابوں کے ساتھ میرا تعلق اتنا ہی تھا کہ سبق میں حاضر ہوتا تھا اور واجبی سے مطالعہ و تکرار کے ساتھ سبق کو کسی حد تک قابو میں رکھنے کی کوشش بھی بسا اوقات کر لیتا تھا، لیکن اس کے علاوہ میری مصروفیات کا دائرہ پھیل چکا تھا اور اس میں شب و روز کی کوئی قید باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس دور میں مدرسہ نصرۃ العلوم کے کتب خانے کے علاوہ عم مکرم حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی لائبریری میری دسترس میں تھی اور چوک نیائیں میں اہل حدیث دوستوں کا ’’اسلامی دار المطالعہ‘‘ میری جولان گاہ میں شامل تھا جہاں میں اکثر عصر کے بعد جاتا، دینی جرائد اور رسالوں پر نظر ڈالتا اور مطالعہ کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب وہاں سے لے آتا۔ طالب علمی کے دور میں سب سے زیادہ استفادہ میں نے ان تین لائبریریوں سے کیا ہے۔
کتاب کے ساتھ تعارف کا اس سے اگلا مرحلہ میرے طالب علمی کے آخری دور میں شروع ہوا۔ یہ ۱۹۶۵ ء کی جنگ کے بعد کے دور کی بات ہے۔ گوجرانوالہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے جہاں آج کل سفینہ مارکیٹ ہے، ان دنوں یہاں خیام ہوٹل ہوا کرتا تھا جہاں ہر اتوار کی شام کو ’’مجلس فکر و نظر‘‘ کے زیر اہتمام ایک فکری نشست جمتی تھی۔ ارشد میر ایڈووکیٹ مرحوم اس مجلس کے سیکرٹری تھے۔ ان سے اسی محفل میں تعارف ہوا جو بڑھتے بڑھتے بے تکلفانہ اور برادرانہ دوستی تک جا پہنچا۔ اس ادبی محفل میں کوئی نہ کوئی مقالہ ہوتا اور ایک آدھ نظم یا غزل ہوتی جس پر تنقید کا میدان گرم ہوتا اور ارباب شعر و ادب اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے۔ پروفیسر اسرار احمد سہاروی، سید سبط الحسن ضیغم، ایزد مسعود ایڈووکیٹ، پروفیسر عبد اللہ جمال، پروفیسر افتخار ملک مرحوم، پروفیسر محمد صادق، پروفیسر رفیق چودھری، اثر لدھیانوی مرحوم اور ارشد میر ایڈووکیٹ مرحوم اس مجلس کے سرکردہ ارکان تھے۔ میں بھی ہفتہ وار ادبی نشست میں جاتا تھا اور ایک خاموش سامع کی حیثیت سے شریک ہوتا تھا۔ ایک روز اگلی محفل کا پروگرام طے ہو رہا تھا لیکن کوئی صاحب مقالہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اگلی محفل میں مضمون میں پڑھ دوں؟ دوستوں نے میری طرف دیکھا تو میری ہیئت کذائی دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوگئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی خاموشی کے بعد ارشد میر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس موضوع پر مضمون پڑھیں گے؟ میں نے جواب دیا کہ ’’فلپ کے ہٹی کی کتاب ’’عرب اور اسلام‘‘ پر ایک تنقیدی نظر‘‘۔ ہٹی کی اس کتاب کا ترجمہ انہی دنوں آیا تھا اور میں نے تازہ تازہ پڑھ کر اس کی بہت سی باتوں کو نشان زد کر رکھا تھا۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ میں اگلے اتوار تک کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات کو قلم بند کر لوں گا مگر میرا یہ کہنا ایک دھماکہ ثابت ہوا۔ میری پہلی بات ہی بعض دوستوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری بات نے تو ان کے چہروں کی کیفیات کو یک لخت تبدیل کر دیا اور مجھے بعض چہروں پر خندۂ استہزا کی جھلک صاف دکھائی دینے لگی، مگر میں اپنے موقف پر قائم رہا جس پر ارشد میر صاحب نے اگلی محفل میں میرے مضمون کا اعلان کر دیا۔
میں نے اپنے مضمون کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں ان واقعاتی غلطیوں کی نشان دہی کی جو ہٹی سے تاریخی طور پر چند واقعات کو بیان کرنے میں ہوگئی تھی اور ان کی تعداد دس سے زیادہ تھی۔ دوسرے حصے میں اس اصولی بحث پر کچھ گزارشات پیش کیں کہ ہٹی اور دیگر مستشرقین اسلام کو ایک تحریک (Movement) کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ اسلام تحریک نہیں بلکہ دین ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی تحریک اور دین کے فرق کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس مضمون کا پہلا حصہ ہفت روزہ ترجمان اسلام لاہور میں اس دور میں شائع ہوگیا تھا مگر دوسرے حصے کے بارے میں ترجمان اسلام کے مدیر محترم ڈاکٹر احمد حسین صاحب کمال مرحوم نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں گم ہوگیا ہے۔ بد قسمتی سے میرے پاس اس کی کاپی نہیں تھی اور مزید بد قسمتی یہ کہ اس کے بعد اس حصے کو لکھنے کی کئی بار کوشش کر چکا ہوں، مگر ابھی تک اس معیار پر نہیں لکھ پا رہا۔ کسی کتاب کے پوسٹ مارٹم اور آپریشن کے حوالے سے یہ میرا پہلا مضمون تھا جو میں نے ’’مجلس فکر و نظر‘‘ کی ہفتہ وار ادبی نشست میں پڑھا جسے بے حد پسند کیا گیا اور اس کے بعد مجلس میں میری شمولیت نے خاموش سامع کے بجائے متحرک رکن کی شکل اختیار کر لی، بلکہ ایک موقع پر ’’اسلام میں اجتہاد کا تصور‘‘ کے عنوان پر مجھ سے مضمون پڑھنے کی فرمائش کی گئی جس پر میں نے بڑی محنت سے ایک مقالہ مرتب کر کے پڑھا۔ یہ نشست پروفیسر اسرار احمد سہارویؒ کی صدارت میں تھی اور شیخ ایزد مسعودنے میرے مقالہ پر اپنی تنقید میں اس کی بعض خامیوں کی نشان دہی کی۔ بعد میں اسی مجلس کے ایک محترم دوست نے وہ مقالہ مجھ سے مطالعہ کے لیے لیا مگر ان کی وفات ہوگئی اور وہ مضمون پھر دستیاب نہ ہو سکا۔
۳۔کون سی شخصیتیں تھیں جنہوں نے آپ کے ذوق مطالعہ کو مہمیز کیا اور اس سفر میں آپ کی رہنمائی کی؟ آپ کے مطالعہ کے مختلف ادوار کیا رہے؟ پسندیدہ موضوعات، ذوق میں ارتقائی تبدیلیاں؟
حضرت والد محترم کے علاوہ چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی اور ماسٹر بشیر احمد صاحب کشمیریؒ بنیادی شخصیات ہیں جنہوں نے مجھے مطالعہ کی طرف راغب کیا، مختلف موضوعات پر کتابیں مہیا کرتے رہے اور میرے مطالعہ کی حوصلہ افزائی اور نگرانی کرتے رہے۔ لکھنے پڑھنے کی عادت طالب علمی کے زمانہ میں ہی تھی۔ مضامین لکھنا، خبریں بنانا اور اخبارات میں پہنچانا اور پھر ان کی اشاعت پر خوش ہونا اسی دور سے مزاج کا حصہ بن گیا تھا۔ اس میں گوجرانوالہ کے معروف صحافی صاحبزادہ سید جمیل الحسن مظلوم مرحوم اور راشد بزمی مرحوم کی حوصلہ افزائی کا بہت دخل رہا ہے۔ اس زمانہ میں پاکستان کے قومی اخبارات میں نسیم حجازی مرحوم کا روزنامہ ’’کوہستان‘‘ خاصی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ ایک بار میرا ایک مضمون روزنامہ کوہستان میں ادارتی صفحہ پر شائع ہوا جس نے میرا دماغ خراب کر دیا اور میں نے دماغ کی اس خرابی میں ایک تعلیمی سال ضائع کر دیا۔ یہ ۱۹۶۵ء کی بات ہے۔ میرے مضامین ہفت روزہ ترجمان اسلام میں شائع ہوتے تھے اور میں روزنامہ وفاق لاہور کا باقاعدہ نامہ نگار بن گیا تھا۔ ’’کوہستان‘‘ کے ادارتی صفحے پر مضمون کی اشاعت نے میرے ذہن میں یہ بات پیدا کر دی کہ میرا اصل میدان صحافت ہے، اس لیے تعلیم و تعلم میں میری توجہ کم ہوتی چلی گئی۔ حضرت والد صاحب نے یہ دیکھ کر مجھے مدرسہ سے اٹھا کر گکھڑ میں گھر لے آئے اور وہاں اپنی نگرانی میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی زمانے میں گکھڑ کے مدرسہ میں استاذ حضرت مولانا غلام علی صاحبؒ سے میں نے فصول اکبری اور گلستان کا کچھ حصہ پڑھا اور حضرت مولانا قاری عبد الحلیم سواتی مدظلہ سے قرآن کریم کے کچھ حصے کی مشق کی۔ حضرت والد صاحب کا انداز سختی کا ہوتا تھا اور سختی کے سارے حربے وہ اختیار کرتے تھے جس سے میں بے بسی کے عالم میں ایک روبوٹ کی طرح تعمیل حکم تو کر لیا کرتا تھا مگر سوچ سمجھ کے دروازے اکثر بند ہی رہتے تھے، اس لیے یہ سختی مجھ پر کچھ زیادہ اثر انداز نہ ہو سکی۔
اس دوران ایک روز گوجرانوالہ میں مدرسہ نصرۃ العلوم میں آیا تو چچا محترم حضرت صوفی عبد الحمید سواتی صاحب ؒ نے پاس بٹھا کر مجھے بڑی شفقت سے سمجھایا اور ان کی یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہوگئی کہ بیٹا! صحافت اور خطابت لوگوں تک کوئی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ضرور آدمی کے پاس ہونا چاہیے، لیکن پہنچانے کے لیے کوئی چیز بھی پاس موجود ہونی چاہیے۔ اگر اپنے پاس کچھ ہوگا تو دوسروں تک پہنچاؤ گے اور اگر اپنا سینہ علم سے خالی ہوگا تو دوسروں کو کیا دو گے؟ ٹونٹی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہی چیز باہر نکالے گی جو ٹینکی میں ہوگی اور اگر ٹینکی میں کچھ نہیں ہوگا تو ’’شاں شاں‘‘ کرے گی۔ حضرت صوفی صاحب ؒ کے اس محبت بھرے لہجے اور ’’شاں شاں‘‘ کی مثال نے ایک لمحے میں دل و دماغ کا کانٹا بدل دیا اور یہ جملے اب بھی میرے کانوں میں ’’شاں شاں‘‘ کرتے رہتے ہیں۔
میرے مطالعہ کاآغاز ’’زندگی‘‘ اور ’’تاریخ احرار‘‘ سے ہوا۔ پھر تاریخی ناولوں کی طرف ذہن مڑ گیا اور نسیم حجازی اور محمد اسلم مرحوم کا مطالعہ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ ہفت روزہ خدام الدین ، ہفت روزہ چٹان اور ہفت روزہ ترجمان اسلام میرے مستقل مطالعہ میں شامل ہوگئے۔ اخبارات بھی شوق سے پڑھتا تھا اور طالب علمی کے زمانے میں نوائے وقت، کوہستان اور امروز میرے روز مرہ مطالعہ کا حصہ ہوتے تھے۔ طالب علمی کے دور میں مطالعہ کے لیے مجھے جس نوعیت کی کوئی کتاب یا رسالہ میسر آجاتا، سمجھ میں آتا یا نہ آتا، میں اس پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش ضرور کرتا۔ البتہ ترجیحات میں بالترتیب مزاحیہ تحریریں، تاریخی ناول اور جاسوسی ادب سر فہرست رہے اور اب بھی اختیاری مطالعہ میں حتی الامکان ترجیحات کی یہ ترتیب قائم رہتی ہے۔ مگر یہ بات تفریحی مطالعہ کی ہے یعنی فارغ وقت گزارنے کے لیے ذہن کو دیگر مصروفیات سے فارغ کرنے کے لیے اور تھوڑی بہت ذہنی آسودگی حاصل کرنے کے لیے، ورنہ عملی و فکری ضرورت کے لیے میرے مطالعہ کی ترجیحات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو چکی ہیں اور اب حدیث نبوی اور اس سے متعلقہ علوم و فنون، تاریخ اور حقائق و واقعات کا پس منظر، اقوام و افکار کا تقابلی مطالعہ اسی ترتیب کے ساتھ میری دلچسپی کے موضوعات ہیں۔
شعر و شاعری بھی میرے مطالعہ کا اہم موضوع رہی ہے اور کسی حد تک اب بھی ہے۔ ایک دور میں دیوان حافظؒ اور دیوان غالب میرے سرہانے کے نیچے مستقل پڑے رہتے تھے۔ دیوان حافظ ؒ کے بہت سے اشعار سمجھ میں نہیں آتے تھے اس لیے میں نے مترجم دیوان رکھا ہوا تھا اور اس کی مدد سے ضروری باتیں سمجھ لیا کرتا تھا۔ عربی ادب میں دیوان حماسہ مطالعہ اور تدریس دونوں کے لیے پسندیدہ کتاب ہے اور مصر کے قومی شاعر شوقیؒ کی کوئی چیز مل جائے تو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شعر گوئی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا، البتہ حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستیؒ ، حضرت والد محترم ؒ اور حضرت چچا محترم ؒ کی وفات پر اپنے جذبات غم منظوم طور پر پیش کیے جو چھپ چکے ہیں اور دوستوں میں پسند کیے گئے ہیں۔
اردو ناول کی شاید ہی کوئی صنف میں نے چھوڑی ہو۔ جاسوسی، تاریخی اور رومانوی ہر قسم کے ناول میں نے پڑھے ہیں ا ور سیکڑوں ناول پڑھ ڈالے ہیں۔ نسیم حجازی سے لے کر ابن صفی تک کوئی ناول نگار میرے دائرے سے باہر نہیں رہا۔ جاسوسی ادب میں ابن صفی اور اکرم الٰہ آبادی میرے سب سے زیادہ پسندیدہ مصنف تھے اور جاسوسی کرداروں میں کرنل فریدی کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ ادبی جرائد میں چٹان، اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، حکایت اور قومی ڈائجسٹ اور علامت سالہا سال تک میرے مطالعہ کا حصہ رہے ہیں۔ معاشرتی، جاسوسی اور تاریخی افسانے بھی بہت پڑھے ہیں اور اب بھی میسر ہوں تو ضرور پڑھتا ہوں۔ کسی رسالہ کے مطالعہ کا آغاز عام طو رپر لطائف کے صفحہ سے ہوتا ہے۔
طالب علمی کے دور میں تعلیم کچھ آگے بڑھی تو حدیث نبوی ؐ کے مطالعہ کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ تاریخ، سیرت اور حدیث نبوی کی کتابیں میرے مطالعہ میں اولین ترجیح تھیں اور اب بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانوی ناول اور طنز و مزاح بھی مطالعہ میں میرے پسندیدہ موضوعات رہے۔ اخبارات کے مزاحیہ کالموں میں شوکت تھانوی، ابراہیم جلیس اور احمد ندیم قاسمی کے کالم شوق سے پڑھتا تھا۔ ان موضوعات پر سیکڑوں کتابیں نظر سے گزری ہوں گی۔ اب جس مطالعہ کا تعلق درس و تدریس اور میری عملی زندگی سے ہے، وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے ہٹ کر تاریخی موضوعات، حدیث نبوی اور اس سے متعلقہ مباحث اور عالمی حالات کے سیاسی تجزیے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وقت کم ملتا ہے اور جوں جوں ’’فرصتے و کتابے و گوشہ چمنے‘‘ کا ذوق بڑھتا جا رہا ہے، اسی رفتار سے مصروفیات میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خواہش بتدریج حسرت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔
میرے لکھنے پڑھنے کے ذوق کو دونوں بزرگوں یعنی والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر ؒ اور عم مکرم حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ کی عملی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں حضرت والد صاحبؒ نے فاتحہ خلف الامام پر اپنی ضخیم کتاب ’’احسن الکلام‘‘ کی تلخیص مجھ سے اپنی نگرانی میں کرائی جو ’’اطیب الکلام‘‘ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس پر دو تین صفحات کا پیش لفظ میں نے خود تحریر کیا جو کتابچہ میں موجود ہے اور مجھے یاد ہے کہ میرے لکھے ہوئے پیش لفظ میں حضرت والد صاحب نے صرف ایک جملہ کی اصلاح کی تھی۔ میں نے ایک جگہ ’’بیک بندش چشم‘‘ کی اصطلاح استعمال کی تھی جسے انہوں نے ’’چشم زدن‘‘ کے محاورہ سے بدل دیا۔ اس کا علاوہ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی جس پر مجھے بے حد خوشی ہوئی اور میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ حضرت صوفی صاحب ؒ نے اپنی تصنیف ’’فیوضات حسینی‘‘ کی تسوید و ترتیب کے کام میں مجھے شریک کیا اور اس کا بیشتر حصہ حضرت صوفی صاحبؒ کی نگرانی میں ان کی ہدایات کے مطابق میں نے مرتب کیا، جس پر مجھے انہوں نے پارکر کا ایک خوبصورت قلم انعام میں دیا۔ دونوں بزرگوں کی یہ خواہش اور کوشش رہی کہ میں ان کے تصنیف و تحقیق کے کام میں معاون اور دست راست بنوں مگر کسی شخص کے لیے اپنے ’’خون کا گروپ‘‘ خود اختیار کرنے کی سہولت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی اور میرے خون کے جراثیم قدرے مختلف تھے، اس لیے اس فطری تنوع نے میری تحریر و تقریر کا میدان کسی حد تک ان سے مختلف کر دیا۔ جمعیت طلبائے اسلام اور جمعیت علمائے اسلام کے پلیٹ فارم پر سیاسی سرگرمیوں میں متحرک ہو جانے کے بعد میرے فکر و نظر کا زاویہ قدرے مختلف ہو چکا تھا اور میرے لکھنے پڑھنے کے موضوعات میں اسلامی نظام کی اہمیت و ضرورت، مغربی فلسفہ و ثقافت کی یلغار، اسلام پر مغرب کی طرف سے کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات و شبہات ، آج کے عالمی تناظر میں اسلامی احکام و قوانین کی تشریح، اسلامائزیشن کے علمی و فکری تقاضے، نفاذ اسلام کے حوالے سے دینی حلقوں کی ضروریات اور ذمہ داریاں، اسلام دشمن لابیوں کی نشان دہی اور تعاقب اور ان حوالوں سے طلبہ، دینی کارکنوں اور باشعور نوجوانوں کی راہ نمائی اور تیاری کو اولین ترجیح کا درجہ حاصل ہوگیا۔ چنانچہ گزشتہ پینتالیس برس سے انہی موضوعات پر مسلسل لکھتا چلا آرہا ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہزاروں مضامین ان عنوانات پر شائع ہو چکے ہیں جن کا انتخاب الشریعہ اکادمی کی ویب سائٹ www.alsharia.org کے مقالات ومضامین کے سیکشن میں موجود ہے۔ کچھ اہم موضوعات پر چند کتابی مجموعے بھی الشریعہ اکادمی نے شائع کیے ہیں۔
۴۔ آپ اُردو کے علاوہ اور کن زبانوں میں مطالعہ کرتے ہیں؟ انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، دیگر زبانیں؟
اردو میرے مطالعہ کا اصل دائرہ ہے۔ عربی میری تدریس کا حصہ ہے، اس لیے زیادہ تر مطالعہ انہی دو زبانوں میں ہوتا ہے۔ فارسی سے معمولی شدبد ہے۔ کتابی فارسی تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں، اس لیے بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اس کے مطالعہ کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، مگر پڑھنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ اگر کوئی چیز مل جائے تو شوق پورا کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ اس کے سوا کوئی زبان نہیں جانتا اور ضروری امور میں تراجم کے ذریعے مقصد پورا کر لیتا ہوں۔
۵۔ آپ کے پسندیدہ مصنفین؟ آپ کی پسندیدہ کتابیں؟ آپ کے پسندیدہ رسائل؟ پسندیدہ افسانہ نگار؟ کالم نگار؟ پسندیدہ مزاح نویس؟ طنز نگار؟
پسندیدہ مصنفین میں مولانا ابو الحسن علی ندویؒ ، چودھری افضل حقؒ ، مولانا مودودیؒ ، مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ ور مولانا مناظر احسن گیلانی ؒ سر فہرست ہیں۔ حدیث نبوی، تاریخ اور سیاسی تجزیہ کی کوئی بھی قابل فہم کتاب میرے نزدیک قابل ترجیح ہوتی ہے۔ کالم نگاروں میں ارشاد احمد حقانی مرحوم، احسان بی اے مرحوم، جاوید چودھری، منو بھائی اور حامد میر کو زیادہ پڑھا ہے اور مزاح نگاروں میں شوکت تھانویؒ ، احمد ندیم قاسمیؒ اور ابراہیم جلیس کو پڑھتا رہا ہوں اور اب یونس بٹ کو پڑھ لیتا ہوں۔
۶۔ آپ اپنی دنیائے مطالعہ میں کس ایک مصنف کو بلند ترین مقام پر رکھتے ہیں جس کا آپ کی ذہنی نشوونما پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہو؟ (خصوصاً اردو لکھنے والوں میں سے؟)
علمی و تحقیقی دنیا میں متقدمین میں امام محمدؒ ، امام بخاریؒ ، ابن تیمیہؒ ، شاہ ولی اللہؒ جبکہ دور حاضر میں والد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر ،ؒ عم مکرم مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ ، مولانا مجاہد الاسلام قاسمیؒ اور الاستاذ وہبہ زحیلی اور فکری دنیا میں علامہ اقبالؒ ، مولانا ابوالحسن علی ندویؒ اور چودھری افضل حق نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔
۷۔ کن کن اخبارات و رسائل کا روزانہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟
کسی زمانے میں چار پانچ اخبارات کا روزانہ بالاستیعاب مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اب وقت نہیں ملتا، اس لیے معمول یہ ہے کہ نوائے وقت، ایکسپریس، پاکستان اور اسلام پر ایک سرسری نظر ڈال کر دلچسپی کی خبر اور کالم تفصیل سے پڑھ لیتا ہوں۔ ’الشریعہ‘ کے تبادلے میں درجنوں جرائد آتے ہیں۔ ان سب کو ایک نظر ضرور دیکھتا ہوں۔ فہرست پر نظر ڈال کر اگر کوئی مضمون دلچسپی یا ضرورت کا ہو تو وہ رسالہ مطالعہ کے لیے الگ کر لیتا ہوں اور اگر موقع مل جائے تو مطالعہ بھی کر لیتا ہوں، ورنہ اس طرح الگ کیے ہوئے رسالے اور کتابیں مہینوں پڑی رہتی ہیں۔
۸۔ کیا دورانِ سفر میں بھی مطالعہ کرتے ہیں؟ اور کس طرح کی کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں؟
دورانِ سفر پہلے مطالعہ کر لیا کرتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ مگر کوئی اخبار یا کتاب ضروری پڑھنی ہو تو اپنے اوپر تھوڑا جبر کر لیا کرتا ہوں۔ کسی سیمینار یا کانفرنس میں گفتگو کے لیے کوئی عنوان میں خود طے کروں یا میرے ذمہ لگ جائے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ تیاری کروں، مگر اکثر اس کا موقع نہیں ملتا۔ وقتی طور پر انتہائی ضروری مطالعہ پر قناعت کرنا پڑتی ہے اور عام طور پر زبانی گفتگو کے بعد اسے قلم بند کرنے کی عادت سی بن گئی ہے۔
۹۔ عام طور پر مطالعہ کے اوقات کیا ہوتے ہیں؟ پروگرام کس طرح چلتا ہے، نشست کس طرح کی پسند کرتے ہیں، رفتار مطالعہ کیا ہوتی ہے؟
اب کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ مصروفیات میں جو وقت بھی نکل آئے، اخبارات و جرائد پر نظر ڈال لیتا ہوں۔ تکیہ کے ساتھ فرشی نشست کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ عام طور پر سیدھا بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ تھکاوٹ ہو تو نیم دراز ہو جاتا ہوں، لیکن لیٹ کر پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔
۱۰۔ آپ کا حافظہ آپ کی وُسعتِ مطالعہ کا کہاں تک ساتھ دیتا ہے، کیا پڑھی گئی کتب کے نام، مضامین، مصنف، پوری طرح یاد رہتے ہیں؟
ضرورت اور دلچسپی کی بات اجمالاً یاد رہتی ہے اور بوقت ضرورت مراجعت میں فائدہ دیتی ہے، لیکن زیادہ تر باتیں ذہن سے عام طور پر محو ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ کہیں دیکھنے پر یاد آتا ہے کہ پہلے بھی یہ بات کہیں پڑھی ہے۔ کسی لائبریری میں جاؤں تو ایک سرسری نظر سب کتابوں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تا کہ کوئی نئی کتاب آئی ہو تو معلوم ہو جائے اور کبھی کسی حوالہ سے کسی کتاب کی ضرورت محسوس ہو تو ذہن میں عام طور پر یہ بات محفوظ رہتی ہے کہ یہ کتاب فلاں لائبریری میں دیکھی تھی۔
۱۱۔ تنہائی اور خاموشی آپ کے مطالعہ کے لیے ضروری ہے، یا آپ ہجوم اور شور و شغب میں بھی پڑھ لیتے ہیں؟
مطالعہ کے لیے تنہائی کی کوشش کرتا ہوں۔ بوقت ضرورت شور و شغب میں بھی کام چل جاتا ہے۔ ایک مرحوم دوست مولانا سعید الرحمن علوی میرے لیے ہمیشہ قابل رشک رہے ہیں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے گپ شپ بھی کرتے تھے، مطالعہ بھی چلتا تھا اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہتے تھے اور ان میں سے کوئی بات دوسری پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ ویسے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب یا رسالہ ہو تو آپ کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔
۱۲۔ کیا مطالعہ کے دوران آپ کتاب پر نشان لگاتے ہیں؟ یا آپ الگ نوٹ کر لیتے ہیں؟ کبھی خلاصہ لکھنے کا شوق رہا؟
کتاب پر نشان لگانے سے گریز کرتا ہوں اور کوئی بات پسند یا ضرورت کی ہو تو نوٹ بک پر درج کر لیتا ہوں۔ کسی کتاب پر حاشیہ لکھنے کا معمول بھی نہیں ہے، البتہ ضروری حوالہ یا عبارت نوٹ بک پر محفوظ کر لیتا ہوں۔ اس قسم کے نوٹس دو تین مختصر کاپیوں میں موجود ہیں جو کبھی کبھی پھر سے دیکھتا رہتا ہوں۔
۱۳۔ آپ اپنے مطالعہ ، حاصلِ مطالعہ اور ذوقِ مطالعہ میں کیا اپنے گھر کے لوگوں خصوصاً بچوں کو بھی حصہ دار بناتے ہیں؟ بچوں کی تربیت ذوق کے لیے آپ کے تجربات کیا ہیں؟
بچوں کو کتاب کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور ان کے مطلب یا ذہنی سطح کی کوئی کتاب نظر آجائے تو مہیا کرتا ہوں اور انہیں مطالعہ کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔
۱۴۔ کیا آپ کی ذاتی لائبریری ہے؟ اس کا حدود اربعہ کیا ہے؟ اس میں اہم ترین کتابیں کون سی ہیں؟ کچھ خاص کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی خاص معرکہ سر کرنا پڑا ہو تو درج فرمائیے؟ نمایاں شخصیتوں کی طرف سے ہدیہ میں آئی ہوئی کتابیں کون کون سی ہیں؟
زندگی میں اپنے جیب خرچ اور کمائی کا ایک بڑا حصہ میں نے کتاب پر صرف کیا ہے۔ ذاتی اور گھریلو اخراجات کے بعد سفر، کتاب، اسٹیشنری و ڈاک میری کمائی کے اہم ترین مصارف رہتے ہیں۔ مجھے جب بھی اپنے اخراجات میں کوئی گنجائش ملی ہے (بسا اوقات اس کے بغیر بھی) تو میری رقم کے مصارف میں یہی تین چیزیں شامل رہی ہیں اور اب بھی یہی صورت حال ہے۔ میں نے زندگی میں جتنی کتابیں خریدی ہیں، اگر سب میرے پاس موجود ہوتیں تو انہیں سنبھالنے کے لیے ایک اچھی خاصی لائبریری درکار ہوتی، مگر میرے ساتھ المیہ یہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک کتاب خریدنے میں جس قدر ’’فضول خرچ‘‘ تھا، اسی طرح کتاب دینے میں بھی فراخ دل رہا ہوں۔ مجھ سے جس دوست نے بھی کسی ضرورت کے لیے کوئی کتاب مانگی ہے، میں انکار نہیں کر سکا اور اس طرح دی ہوئی کتابوں میں شاید ہی چند کتابیں مجھے واپس ملی ہوں، ورنہ اکثر کتابیں دوستوں ہی کے کام آرہی ہیں۔ یہ ’’واردات‘‘ میرے ساتھ انفرادی کے علاوہ اجتماعی بھی ہوئی ہے اور کئی بار ہوئی ہے۔ ۱۹۶۵ء کی بات ہے کہ گکھڑ میں ’’انجمن نوجوانان اسلام‘‘ قائم ہوئی جس کے بانیوں میں میرا نام بھی شامل ہے۔ اس انجمن نے عوامی خدمت کے لیے ’’دار المطالعہ‘‘ قائم کیا تو میں نے اپنی زیادہ تر کتابیں وہاں دے دیں کہ عمومی استفادہ ہوگا اور محفوظ بھی رہیں گی، مگر دو چار سال کے بعد انجمن بکھری تو کتابوں کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئیں۔
اس کے بعد گوجرانوالہ میں اسلامیہ کالج روڈ پر کچھ نوجوانوں نے ’’انصار الاسلام لائبریری‘‘ کے نام سے ایک دینی دار المطالعہ قائم کیا تو اس وقت جمع ہونے والی کتابوں کا بڑا حصہ ان کی نذر کر دیا۔ یہ دار المطالعہ آٹھ دس سال چلتا رہا اور اب اس کا بھی کوئی سراغ موجود نہیں ہے۔ اس کے کافی عرصہ بعد شاہ ولی اللہ یونیورسٹی وجود میں آئی اور اس میں لائبریری قائم کی گئی تو میں نے ایک بار پھر کتابوں کی چھانٹی کی اور اچھا خاصا ذخیرہ شاہ ولی اللہ یونی ورسٹی کی لائبریری میں منتقل کر دیا، مگر یونیورسٹی کا سلسلہ تعلیم چند سال بعد منقطع ہوگیا تو لائبریری بھی بند ہوگئی۔ خدا جانے کوئی کتاب اب وہاں موجود ہے یا نہیں۔ اب میری ساری توجہ الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ کی لائبریری کی طرف مبذول ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھی سی لائبریری اصحاب ذوق کو میسر آجائے۔ اس کارِ خیر میں عزیزم محمد عمار خان ناصر سلمہ بھی میرے ساتھ شریک ہے جو کتابی ذوق سے بخوبی بہرہ ور ہے اور لکھنے پڑھنے کے سوا اس کی کوئی اور دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا بڑا بیٹا طلال خان بھی کتابوں اور رسالوں میں ہی غرق رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانا بھی ماشاء اللہ اس کیفیت میں کھاتا ہے کہ کتاب یا رسالہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پاس بیٹھی ماں یا دادی اس کے منہ میں لقمے ڈالتی رہتی ہے۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائیں۔ مجھے اور عمار میں سے جس کو بھی کوئی کتاب میسر آجائے اور وہ ہماری وقتی یا ذاتی ضرورت کے دائرہ کی نہ ہو تو الشریعہ اکادمی کی لائبریری کی نذر ہو جاتی ہے۔ ’’الشریعہ اکادمی‘‘ کی لائبریری کو بہت چھوٹی ہونے کے باوجود شہر کی اہم لائبریریوں میں بحمد اللہ تعالیٰ شمار کیا جا سکتا ہے۔
بعض کتابوں کے حصول میں غیر معمولی صورت حال سے بھی واسطہ پڑا۔ میری طالب علمی کے زمانے میں مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے ایک شاگرد مولانا محمد صدیق ولی اللہی وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے۔ مجذوب طرز کے بزرگ تھے، مگر کتاب کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے اور کوئی نہ کوئی نادر کتاب ان کے تھیلے میں موجود ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ان کے پاس ہندوستان کی زمینوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں مولانا محمد اعلیٰ تھانوی کا رسالہ دیکھ لیا جو ان دنوں نایاب تھا۔ مجھے اس کی تلاش تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ چند روز کے لیے مرحمت فرما دیں، میں نقل کر لوں گا۔ انھوں نے انکار کر دیا۔ میں نے گزارش کی کہ رات آپ نے یہیں رہنا ہے، اس لیے ایک رات کے لیے دے دیں، صبح واپس کر دوں گا۔ انھوں نے وہ رسالہ مجھے اس شرط پر دے دیا۔ میں نے رات بھر جاگ کر وہ رسالہ نقل کر لیا اور صبح کو انھیں واپس کر دیا۔
صدر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل نے سود کی حرمت اور اس کے متبادل شرعی نظام کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی تھی۔ ان دنوں اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹوں کی اشاعت پر پابندی ہوا کرتی تھی۔ مجھے اس رپورٹ کی تلاش تھی اور معمول کے ذرائع سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی، البتہ قومی اسمبلی کے ارکان میں وہ تقسیم کی گئی تھی۔ میں ایک دن بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ایک رکن سے، جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، ملنے کے لیے ایم این اے ہاسٹل میں ان کے کمرے میں گی تو وہ رپورٹ ان کی میز پر پڑی دیکھی۔ میرا جی للچایا اور میں نے ان جانے سے انداز میں ان سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ انھوں نے بھی اسی انجانے سے لہجے میں کہا کہ پتہ نہیں، کوئی صاحب دے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی ضرورت کی تو نہیں، کیا میں لے لوں؟ انھوں نے اثبات میں سر ہلایا تو میں نے وہ کتاب اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ اس رپورٹ کے اس طرح اچانک حصول پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے محفوظ کر لیا کہ برطانیہ کے سفر کے دوران فراغت سے مطالعہ کر لوں گا، مگر ساؤتھال لندن کی ابوبکر مسجد میں ورلڈ اسلامک فورم کی ایک میٹنگ میں انڈیا کے محقق عالم دین حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمیؒ ہمارے ساتھ شریک تھے۔ میں نے کسی ضرورت کے تحت اپنا بیگ ان کے سامنے کھولا تو ان کی نظر اس رپورٹ پر پڑ گئی۔ انھوں نے مجھ سے مانگ لی اور فرمایا کہ میں تو ایک عرصہ سے اس کی تلاش میں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے بھی بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ انھوں نے یہ فرما کر بے تکلفی کے ساتھ وہ رپورٹ اپنے بیگ میں رکھ لی کہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، تم کوئی اور نسخہ تلاش کر لینا۔ مجھے کتاب کھو جانے کا افسوس تو ہوا، مگر اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ رپورٹ مجھ سے زیادہ اہل اور مستحق بزرگ کے پاس پہنچ گئی۔
لندن ہی میں ورلڈ اسلامک فورم کے سیکرٹری جنرل مولانا مفتی برکت اللہ کی ذاتی لائبریری میں ایک کتاب میری نظر سے گزری جو ایک عرب محقق الاستاذ عبد الحلیم ابو شقہ ؒ نے ’’تحریر المراۃ فی عصر الرسالۃ‘‘ کے عنوان سے چار جلدوں میں لکھی ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتوں کو حاصل ہونے والی آزادیوں کے بارے میں انتہائی مستند مواد جمع کر دیا ہے۔ انسانی حقوق اور خاص طو رپر عورتوں کے حقوق میر ے مطالعہ اور گفتگو کا ہمیشہ سے اہم موضوع رہے ہیں، اس لیے یہ کتاب میری دلچسپی اور ضرورت کی تھی۔ میں نے مولانا مفتی برکت اللہ کے ساتھ وہی کیا جو میرے ساتھ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی نے کیا تھا۔ مفتی برکت اللہ صاحب کے نہ نہ کرتے بھی میں نے وہ کتاب اپنے بیگ میں رکھ لی اور ان سے کہا کہ آپ دوسرا نسخہ منگوا لیں، یہ میں لے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ الشریعہ اکادمی کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کتاب کا مکمل اردو ترجمہ اب اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام آباد سے شائع کر دیا ہے، جبکہ ایک جلد میں اس کی تلخیص بھی ’’عورت عہد رسالت میں‘‘ کے عنوان سے لاہور کے ایک اشاعتی ادارے نے شائع کی ہے۔
یہودیوں کی ایک اہم کتاب ’’تالمود‘‘ ہے جس کا وہ عام طو رپر مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مجھے اس کی تلاش تھی کہ ا س کا اردو یا عربی ترجمہ مل جائے تو یہ معلوم کر لوں کہ مواد کس نوعیت کا ہے۔ مختلف دوستوں سے پوچھتا رہا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ برطانیہ میں ایک کتاب شناس دوست سے ذکر کیا تو انھوں نے بتایا کہ ’تالمود‘‘ کے منتخب حصوں کا اردو ترجمہ تو آپ کے گوجرانوالہ سے شائع ہوا ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انھوں نے اپنی لائبریری سے وہ کتاب نکال کر مجھے دکھائی تو اس پر ناشر کے طور پر ’’بیت المومنین سادھوکی گوجرانوالہ‘‘ لکھا تھا۔ واپسی پر میں نے سادھوکی کے قریب جی ٹی روڈ پر واقع جامعہ اسلامیہ کے مہتمم مولانا عبد الرؤف فاروقی کو بتایا تو انھیں بھی حیرانی ہوئی۔ہم دونوں سادھوکی کے ریلوے پھاٹک کے ساتھ واقع ادارہ ’’بیت المومنین‘‘ پہنچے تو دیکھا کہ وہ کیتھولک مسیحیوں کا ایک عالمی سطح کا معیاری اشاعتی ادارہ ہے جہاں سے ویٹی کن سٹی کی مطبوعات کے معیاری اردو تراجم شائع ہوتے ہیں۔ عجیب اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس وقت جو انچارج پادری صاحب وہاں موجود تھے، ان کا تعلق بھی ہمارے آبائی شہر گکھڑ سے تھا۔ انھوں نے ہمیں پہچان لیا، خوب آؤ بھگت کی اور تالمود کے اردو ترجمے کے علاوہ کیتھولک بائبل اور چند دیگر کتابیں بھی ہمیں ہدیے کے طو رپر پیش کیں۔
آج کل مطلب کی کسی کتاب کے حصول کے لیے مجھے عام طو رپر تین ذرائع میسر ہیں۔ کسی صاحب علم دوست کے ہاں جاتا ہوں تو ان کی لائبریری پر ایک نظر ضرور ڈالتا ہوں۔ کوئی نئی کتاب دلچسپی کی نظر میں آئے تو اس کا نام اور مصنف وناشر کا تعارف ذہن نشین کر لیتا ہوں اور بعد میں موقع ملے تو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ ہمارے دوستوں میں ایک کتاب دوست اور کتاب شناس ساتھی شبیر احمد میواتی ہیں۔ اچھی کتابوں کی تلاش، ان کا حصول اور متعلقہ دوستوں تک انھیں پہنچانا (اگرچہ بعض اوقات اس کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے) میواتی صاحب کا خصوصی مشغلہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر آتے رہتے ہیں اور ہر مرتبہ ان کی زنبیل میں نئی اور پرانی کتابوں کا ایک اچھا انتخاب موجود ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی کتاب میرے مطلب کی ہو تو وہ دے دیتے ہیں یا میں مانگ لیتا ہوں، ورنہ مطالعہ کے لیے تو رکھ ہی لیتا ہوں جو زیادہ تر واپس بھی کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک اور دوست محمد رفیق صاحب ہیں۔ نادر عربی کتابوں کی خرید وفروخت ان کا مشغلہ ہے۔ کبھی کبھی آتے ہیں تو ان کا تھیلا کھلوا کر دیکھتا ہوں۔ کوئی دلچسپی یا ضرورت کی کتاب جیب کی گنجائش کے دائرے میں ہو تو خرید لیتا ہوں یا عمار سے کہتا ہوں کہ الشریعہ اکادمی کے فنڈ میں گنجائش ہو تو لائبریری کے لیے خرید لو۔ بصورت دیگر کتاب خاموشی کے ساتھ واپس کر دیتا ہوں۔
۱۵۔ کتابیں مستعار دینے اور لینے کے متعلق آپ کے تجربات کیا ہیں اور اس معاملے میں آپ کا نظریہ و مسلک کیا ہے؟ کیا کچھ واقعات ایسے ہیں کہ بعض اہم کتابوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے ہوں؟
اس بارے میں بہت تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ بہت سی کتابیں ضائع کر چکا ہوں۔ ایک اہم کتاب جو مجھ سے کسی صاحب نے مطالعہ کے لیے لی، کئی برس بعد مجھے ایک فٹ پاتھ پر کتابیں بیچنے والے سے دوبارہ خریدنی پڑی۔ حتی کہ فلپ کی ہٹی کی جس کتاب کا میں سطور بالا میں ذکر کر چکا ہوں، اس پر میرے لکھے ہوئے نوٹس بھی موجود تھے، وہ اور قاضی عیاضؒ کی ’’الشفاء‘‘ جو ایک دوست نے مجھ سے مطالعہ کے لیے لی تھیں، یہ دونوں ذاتی کتابیں میں نے فٹ پاتھ سے دوبارہ خریدیں۔
۱۶۔ کیا مطالعہ سے عمر کے ساتھ ساتھ کوئی ذہنی، فکری تبدیلی پیدا ہوئی؟
مطالعہ کے ارتقا سے فکر و ذہن کا ارتقا ایک فطری امر ہے۔ میں بھی اس تجربہ سے دو چار ہوا ہوں۔ بہت سی باتیں جن پر ابتدائی دور میں لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے، اب ہلکی پھلکی معلوم ہوتی ہیں اور مطالعہ نے رفتہ رفتہ فکر میں توسع اور تنوع پیدا کیا ہے۔ خاص طور پر یہ کہ آج کے حالات میں آزادانہ بحث و مباحثہ کے بغیر کسی بھی مسئلے میں منطقی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ اور تعلیمی مراکز نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مختلف اطراف سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو مہم شروع کر رکھی ہے، اس کے اثرات سے نئی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارا روایتی اسلوب کافی نہیں ہے۔ ماضی نے اپنا علمی خزانہ کتابوں اور سی ڈیز کی شکل میں اگل دیا ہے اور آج کوئی بھی ذی استعداد اور با صلاحیت نوجوان اپنے چودہ سو سالہ علمی ماضی کے کسی بھی حصہ کے بارے میں معلومات حاصل کر نا چاہے یا کسی بھی طبقے کا موقف اور دلائل معلوم کرنا چاہے تو اسے اس کے بھرپور مواقع اور وسائل ہر وقت میسر ہیں۔ اس ماحول میں یہ کوشش کرنا کہ نوجوان اہل علم صرف ہمارے مہیا کردہ علم اور معلومات پر قناعت کریں اور علم اور معلومات کے دیگر ذرائع سے آنکھیں اور کان بند کر لیں ، نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں بلکہ فطرت کے بھی منافی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ہماری ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بات ہمارے فرائض میں شامل ہو جاتی ہے کہ مطالعہ اور تحقیق کے اس سمندر سے نئی نسل کو روکنے کی بجائے خود بھی اس میں گھسیں اور ان متنوع اور مختلف الجہات ذرائع معلومات میں حق کی تلاش یا حق کے دائرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی راہ نمائی کریں۔ چنانچہ علم و فکر کی دنیا میں میرا ذوق روکنے یا باز رکھنے کا نہیں بلکہ سمجھانے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کا ہے۔ کسی دوست کو یہ طریقہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے بحث و مباحثہ ضروری ہے، مسائل کا تجزیہ و تنقیح اور دلائل کی روشنی میں ان کا خالص علمی انداز میں تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایک عرصہ تک میرا بھی یہ ذوق اور ذہن رہا ہے کہ تحقیق کا دائرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم اپنے ذہن میں پہلے سے طے کر چکے ہیں، اسے کسی نہ کسی طرح ثابت کر دیا جائے۔ مگر رفتہ رفتہ یہ بات ذہن میں راسخ ہوتی گئی کہ خود اپنی بات کو دلائل اور حقائق کے معیار پر پرکھنا بھی تحقیق کا اہم ہدف ہوتا ہے ۔ بہت سے مسائل میں اکابر اہل علم کا رجوع الی الحق بالخصوص حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی طرف سے اس کا باقاعدہ اہتمام میرے ذوق میں اس تبدیلی کا باعث بنا۔
۱۷۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ باقی دنیا سے کٹ گئے ہوں اور آپ کو باقی زندگی کے لیے (قرآن مجید کے علاوہ) صرف تین کتابوں کے انتخاب کا موقع دیا جائے تو کن کتابوں کا انتخاب کریں گے؟
اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورت پیش آئے، لیکن اگر خدانخواستہ کوئی ایسی صورت پیش آجائے تو قرآن کریم کے علاوہ احادیث نبویہ کے کسی اچھے سے مجموعہ، تاریخی واقعات کی کوئی ضخیم کتاب اور دیوان سنگھ مفتون کی ’’ناقابل فراموش‘‘ کا تقاضا کروں گا۔
۱۸۔ کیا کبھی کسی تحریر کے مطالعے سے منفی احساس بھی ہوا، مایوسی یا غصے کی کیفیت؟
قرآن کریم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام اور بڑی دینی شخصیات کا کہیں توہین و تمسخر کے انداز میں ذکر ہو تو غصہ آتا ہے اور وہیں مطالعہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اختلاف رائے کا حق بلا جھجھک استعمال کرتا ہوں اور بلا تأمل دوسروں کو اختلاف رائے کا حق دیتا ہوں۔ سنجیدہ علمی اختلاف کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں، مگر توہین، استہزا اور تمسخر میرے لیے ہمیشہ ناقابل برداشت رہا ہے اور استحقار واستخفاف کا لہجہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اختیار کیا جائے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تنقید واعتراضات پر مشتمل پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب ’’ستیارتھ پرکاش‘‘ کے چودھویں باب کا کئی بار مطالعہ کیا ہے اور اب بھی ضرورت پڑنے پر اسے دیکھتا ہوں، مگر راج پال کی بدنام زمانہ کتاب ’’رنگیلا رسول‘‘ کو پڑھنے کا اپنے اندر کبھی حوصلہ نہیں پایا۔
۱۹۔ کچھ ایسے مصنفین جن کو ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا ہو، ملاقات میں کامیاب ہوئے، ملنے کے بعد تاثرات؟
اقبال اور چودھری افضل حق تو میری ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، البتہ مولانا ابوالحسن علی ندوی ؒ اور الاستاذ وہبہ زحیلی سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی زیارت پہلی بار ۱۹۸۴ء کے دوران مکہ مکرمہ میں کی جہاں وہ مولانا محمد منظور نعمانیؒ کے ہمراہ غالباً رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کی سعادت حاصل کرنے کے علاوہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں بیت اللہ شریف کا طواف کرانے کا شرف بھی حاصل کیا۔ مولانا ندویؒ سے بعد میں میرا بیعت کا تعلق قائم ہوا اور انہوں نے تحریری طور پر اپنی تمام اسناد کے ساتھ روایت حدیث نبوی ؐ کی اجازت کے شرف سے بھی نوازا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔ امریکی مصنف ’’ڈیل کارینگی‘‘ بھی میرے پسندیدہ مصنفین میں سے ہیں مگر ملاقات کا موقع نہیں مل سکا ، شاید وہ بھی میری ہوش کی عمر سے پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے ہوں۔ نسیم حجازی مرحوم سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ مولانا مودودیؒ سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمیؒ کے ساتھ برطانیہ میں گزرے ہوئے چند دن میری زندگی کے یادگار ایام میں سے ہیں۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ کے ساتھ ملاقات بھی خوشی کا باعث بنی، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہؒ کی زیارت وملاقات کی زندگی بھر حسرت رہی۔
مکاتیب
ادارہ
محترم ومکرم جناب مدیر صاحب، ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ
السلام علیکم! امید ہے کہ جناب مع الخیر ہوں گے۔
میں گزشتہ کچھ سالوں سے جناب کے موقر جریدے کا ایک ادنیٰ قاری ہوں۔ ا س میں شائع ہونے والی اکثر تحریریں بہت اچھی ہوتی ہیں اور مختلف موضوعات پر دینی تناظر میں گفتگو کو آگے بڑھانے میں معاون ہوتی ہیں۔ اگرچہ دل بہت چاہتا ہے کہ ’’الشریعہ‘‘ میں شائع ہونے والی تحریروں کا اسلوب علمی ہوتا اور ان کی فکری سطح بھی کچھ بلند ہوتی، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی میرے دل میں بہت عزت ہے کہ ہمارے آج کے تہذیبی ویرانے میں ’’الشریعہ‘‘ ایک توشہ خاص ہے۔
آپ کے جریدے میں جولائی اور اگست کے شماروں میں ایک مضمون ’’تنقیدی جائزہ یا ہجو گوئی‘‘ از جناب محمد رشید صاحب دو قسطوں میں شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے جناب میاں انعام الرحمن کے مضمون پر بڑی سخت گرفت کی ہے۔ میں اسی حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اعترافات کرتا چلوں تو مناسب ہوگا۔
میں جناب میاں انعام الرحمن اور جناب محمد رشید میں سے کسی سے ذاتی طور پر واقف نہیں ہوں۔ میں اپنی معروضات کو صرف اسی مضمون پر اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ میں ڈاکٹر محمود غازی مرحوم کے لیے بہت نیک جذبات رکھتا ہوں، اگرچہ میں ذاتی طو رپر ان سے واقف نہیں تھا۔ میرے حلقہ احباب میں کچھ لوگ ان کے بارے میں بہت حسن ظن رکھتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہوا ہے۔ وہ بہت متقی اور نیک آدمی تھے۔ اللہ انھیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ان کی نیکی کی خبر پر یقین کے بعد میں نے ان کی چند تحریروں کو دیکھا، لیکن ان میں سے مجھے کوئی بھی کام کی نہیں لگی، لیکن الحمد للہ ان کے بارے میں اچھے جذبات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں تقویٰ اور علم کو نہ مساوی سمجھتا ہوں نہ لازم وملزوم جانتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ تقویٰ ضروری چیز ہے اور مدار نجات ہے، جبکہ علم کو یہ حیثیت بھی حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر غازی مرحوم کا تقویٰ اللہ کے ہاں ان شاء اللہ مقبول ہوگا اور ان کے علم میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ کوئی ایسی گھبرانے کی یا سیخ پا ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ چلیں، اگلی نسل میں اس پر بات آگے بڑھے گی تو ان موضوعات کے زیادہ بہتر اور قابل توجہ پہلو سامنے آئیں گے جن پر ڈاکٹر صاحب کی نظر نہیں گئی تھی۔ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ڈاکٹر غازی مرحو م کے تقویٰ اور علم میں خلط مبحث پیدا کرنا، امت کے لیے ان کی دردمندی کو فراموش کرنا، امت مسلمہ کی علمی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کی نیک نیتی پر شک کرنا یا یہ سمجھ لینا کہ ان کی کوششوں سے یہ علمی ضروریات کسی درجے میں پوری ہو گئی ہیں، میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر غازی مرحوم یا کسی بھی دین دار آدمی کے تقویٰ کو زیر بحث لا کر اپنی عاقبت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔
ان گزارشات کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جناب محمد رشید کے اس رویے کی بالکل سمجھ نہیں آئی جو انھوں نے جناب میاں انعام الرحمن کے حوالے سے ظاہر کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے علما کے نظری، فکری اور علمی افلاس کو دین ہی کا کوئی حصہ سمجھ رکھا ہے تو پھر یہ رویہ بالکل درست ہے اور عین ایمان ہے۔ مجھے علما کے دینی علم میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر وہ کتابیں یاد کر کے کچھ چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں تو یہ ان کا علم نہیں قرار پائے گا۔ صرف یہی کہیں گے کہ معلومات ان کی اچھی ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علما عصر حاضر میں ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمتوں کاظہور تھا، لیکن تقسیم کے بعد ہمارے علما اور مذہبی طبقے نے عوام کے حقوق اور مفادات پر استعماری سرمایے، استعماری علم اور استعماری سیاست سے جس جس طرح کی سودے بازی کی ہے، وہ بھلا کس سے اوجھل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں جو آدمی علما سے علم کا مطالبہ کرے یا مسلمانوں کے لیے کسی طرح کے اخلاقی لوازم کی بات کرے، اس کی سرکوبی کا مستقل بندوبست ہونا چاہیے۔ ا س مطالبے کے غیر دینی ہونے کو بھی اب سے نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر طرح کی دینی تعبیرات کو ایک سازگار فضا میسر آ سکے اور ایسی ہر صورت حال کے خاتمے کی محکم تدابیر ہونی چاہییں جس سے مسلمانوں میں علمی گفتگو کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہو۔ اس سے ہماری مجموعی insecurity کو ختم کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔
اب جناب میاں انعام الرحمن کی جس پہلی ہی بات پر جناب محمد رشید نے اتنے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ہمارے علما کا اور دینی ڈسکورس میں بات کرنے والوں کا عمومی رویہ ہے۔ اب اس میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر غازی مرحوم جو علمی زاد راہ لے کر عصر حاضر پر گفتگو کرنے نکلے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس سے ان کی نیک نیتی اور تقوے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر وہ کچھ چیزوں کا سرے سے ہی کوئی علم نہیں رکھتے تو اس میں کوئی حرج والی بات کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث سے یقیناًواقف ہیں، لیکن جس طرح اس کی تطبیق کر رہے ہیں، وہ قطعی غیر علمی ہے۔ اس میں کیا قیامت آ گئی؟ اس سے مسلمانوں کا بھلا ہی ہوا کہ وہ کوشش جاری رکھیں گے اور اس کی بہتر تطبیق کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے جو علمی طو رپر قابل دفاع ہو۔ میرا خیال ہے کہ نظری اور فکری امو رپر فقہی ذہن سے فتویٰ لگانا ہمارے ہاں مذہبی علم کی معراج ہے، لیکن بدلے ہوئے عصری حالات میں اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں۔ نظری اور فکری افلاس کو فقہی احکامات کی گوشہ وار تفصیل بیان کرنے سے پر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جناب میاں انعام الرحمن نے دو مستثنیات کیساتھ ایک سخت بات کہی ہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے تدارک کی کوئی سبیل نکالنی چاہیے۔
یہ مولانا صاحب تو چلیے، نظام معاش پر فقہی معلومات اور عصری بے خبری میں کچھ کلام کرنے نکلے ہیں۔ تعلیم ہمارے لیے کیا کچھ اہمیت نہیں رکھتی! لارڈ میکالے کے جس نظام تعلیم پر، جس نے ہماری عصری شعور کی بہت گہرائی میں تشکیل کی ہے اور ہمارے شعورکی پوری ساخت ہی کو غیر انسانی، غیر فطری اور غیر دینی بنیادوں پر استوار کیا ہے اور علما کا کام بھی یہی تعلیم تھا تو اس پر کوئی ایک علمی فقرہ بھی پچھلے تقریباً دو صد سالوں میں لکھا گیا ہے؟ میں یہاں سیاسی نعرے بازی کا ذکر نہیں کر رہا۔ وہ تو بہت ہوئی ہے کہ لارڈ میکالے فلاں، لارڈ میکالے ڈھماں۔ میں نے متداول مدارس کے نظام کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے اور اللہ سے ڈر کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ علما قیامت کے دن اسی میں دھرے جائیں گے۔ اللہ معاف کر دے تو اور بات ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ ہمارے علما کو جدید تعلیم اور جدید عہد میں دی جانے والی کسی بھی طرح کی تعلیم کی کوئی ابجدی واقفیت بھی نہیں ہے۔ دین دار ہونا اور چیز ہے، تعلیم دینا، بھلے وہ دینی ہو یا غیر دینی، اور بات ہے۔ اگر بظاہر کوئی اچھے دینی ادارے نظر بھی آ رہے ہیں تو سب ریس اور نقل پر قائم ہو رہے ہیں اور مغربی تعلیم کی دین کے آنگن میں پیش رفت کے نئے سنگ میل ہیں۔ تعلیم کی آڑ میں سب سیاست بازی ہے۔ ہمارے علما تعلیم کے نہ انسانی پہلووں سے باخبر ہیں نہ اس کے فنی پہلووں سے آگاہ ہیں اور جدید تعلیم کے نظری اور فکری پہلووں کی تو موجودگی کی بھی ان کو خبر نہیں ہے۔ اب ’’دینی تعلیم‘‘ کی ترکیب ہی ایسی ہے کہ عام آدمی سہم جاتا ہے کہ اگر کوئی بات کہہ دی تو کہیں ایمان ہی سے نہ فارغ کر دیا جائے۔ میں یہاں نورانی قاعدے کے مولف مولانا نور محمدؒ خلد آشیانی کے چند فقرات لکھ رہا ہوں۔ غور فرمائیے گا:
’’جب تک اتنی مشق نہ ہوجائے، آگے نہ پڑھائیں۔ ورنہ وہی مثل صادق آئے گی، آگا دوڑ پیچھا چوڑ۔ اگر کوشش اور محنت سے پڑھا نہیں سکتے تو ناحق بچوں کی عمر اور استعداد برباد نہ کریں۔ اس کا گناہ چوری اور راہزنی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مال واسباب پھر بھی مل سکتا ہے، لیکن گزری ہوئی عمر واپس نہیں آ سکتی اور بگڑی ہوئی استعداد درست نہیں ہوتی۔‘‘
جناب محمد رشید صاحب نے یہ ثابت کرنے میں بہت زور لگایا ہے کہ ڈاکٹر غازی صاحب قارونی نظام کے سخت مخالف تھے اور انھوں نے جو پیرا گراف حوالہ قرطاس کیے ہیں، ان سے تویہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قارونی نظام کے بہت خلاف ہے۔ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، کیونکہ دین اسی کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ بہت دین دار آدمی تھے۔ لیکن قارونی نظام کا کوئی فہم ڈاکٹر صاحب کی محولہ تحریروں میں موجود نہیں ہے۔ اگر قارونی نظام کی دشمنی کے دینی مطالبات کسی علمی فہم میں بھی تبدیل نہیں ہوتے تو یہ بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب دین کی مراد پر قائم ہو گئے تھے تو ہمیں یہ بھی تسلیم ہے اور حسن ظن بھی یہی ہے، لیکن اس بات کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ دین کی روحانی اور اخلاقی اقدار کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو فطری ہیں۔ اور پھر اس اصرار کی کیا گنجائش ہے کہ ان اقدار کو ماننے والا ازخود نظری اور فکری مطالبات اور مرادات تک رسائی بھی حاصل کر لیتا ہے؟ یعنی ایک متقی آدمی صاحب علم بھی ازخود بن جاتا ہے اور تقویٰ ازخود سیاسی اور علمی سیادت میں بھی بدل جاتا ہے؟ انھی خوش فہمیوں میں ہمارے علما اس امت کو عصر حاضر کے ظلمت خانوں میں لے کر پہنچے ہیں جہاں اب خود انھیں بھی کوئی راستہ سجھائی نہیں د ے رہا، اگرچہ واویلا اس کے برعکس مچایا جا رہا ہے۔ اور اب چاروں طرف تہذیب مغرب کو، ا س کے چند بالکل اسلام مخالف پہلووں کے علاوہ، justify کرنے کا شدید ترین داعیہ بھی ہمارے دینی طبقے ہی سے ابھر رہا ہے۔
مدیر صاحب! اب بازی ہمارے ہاتھ سے آخرکار مکمل نکل گئی ہے، کیونکہ علما نے سیاست بازی میں بڑا وقت ضائع کیا ہے اور اپنے اصل کام یعنی دین کے علمی دفاع سے بہت سخت نوعیت کی غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب علما کو دین اور نفس دین کی فکر نہیں ہے، ان کو اب اپنی فکر لگ گئی ہے اور یہ سب اسی کے اظہارات ہیں۔ کیا یہ طرفہ تماشا نہیں کہ کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگ جو دین کا درد بھی رکھتے ہیں، اب مغرب کے خلاف دفاعی پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور علما اپنی تحریروں میں صبح شام وہ مقامات اور اقوال نکال نکال کر دکھا رہے ہیں جن سے مغرب کو جواز ملتا ہے؟ تقسیم کے بعد، چند ایک حق پرست علما کو چھوڑ کر، ہمارے وہ کون سے علما ہیں جنھوں نے آمریت اور استعمار کے در پر جبیں سائی نہیں کی ہے، جنھوں نے تیرہ آشام تعلیم اور علم کو اپنے فتاویٰ سے جواز نہیں بخشا ہے، جنھوں نے ظلم، جبر اور استبداد کو مذہبی جواز دے کر سیاسی اسلام کو عوام کے حقوق کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے؟
ڈاکٹر صاحب کے جو بھی اقتباسات جناب محمد رشید نے درج فرمائے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ ان کے مشمولات سے بھلا کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بڑی صحافیانہ سی باتیں ہیں جو عام سیاسی مجلوں میں آئے دن چھپتی رہتی ہیں۔ ان میں کوئی نظری، فکری یا علمی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات جناب میاں انعام الرحمن نے بھی کہہ دی ہے تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ اگر ڈاکٹر صاحب مغرب پر تنقید کر رہے ہیں تویہ بھی اچھی بات ہے اور ان کی یہ تنقید بھی درست ہے اور اس کا تناظر اخلاقی اور سیاسی ہے اور یہ ہمارے کچھ طبقات میں متداول بھی ہے۔ لیکن یہ عام سی باتیں ہیں جو ہم صبح شام اپنے ارد گرد سنتے رہتے ہیں۔ ان باتوں کے لیے وہ عند اللہ ماجور بھی ضرور ہوں گے، لیکن یہ شور مچانا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی علمی بات بیان فرمائی ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اورجناب انعام کی تحریر میں مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے ڈاکٹر صاحب کی ذاتی تنقیص کا کوئی پہلو سامنے آتا ہو۔
اخلاقی وعظ نگاری کو پچھلے دو سو سال سے لکھتے پڑھتے، ہم اسی کو اب علم پر بھی محمول کرتے ہیں۔ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ وہ بات ہاتھ لگے جس پر رد عمل میں جناب محمد رشید صاحب نے ہر اخلاقی حد عبور کی ہے، سوائے اس بات کے کہ جس شخصیت کے ساتھ ’’مولانا‘‘ ]ایک زمانہ تھا جب انگریزی میں ’’ڈاکٹر‘‘ کا اصل مفہوم مولانا ہی تھا[ لگا ہو، اس کے خیالات پر بات کرنے سے احتراز کرنی چاہیے، بس ایمان لے آنا چاہیے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ اخلاقیات جس طرح ہمارے انفرادی اور اجتماعی عمل سے خارج ہو گئی ہے، اسی طرح دین کی گفتگو سے بھی بالکل غیرمتعلق ہو چکی ہے۔ بد کلامی، پوچ گوئی، اتہام، الزام بازی اور بد تہذیبی کیا کوئی نیک عمل بن جاتا ہے اگر میں اس کے ساتھ ’’دینی‘‘ کا لفظ اضافہ کر دوں؟ عصر حاضر میں دائرۂ کفر واسلام کمزو رپڑ جانے پر اب دینی گفتگو میں گالم گلوچ کی نئی اہمیت سامنے آ رہی ہے۔ جناب انعام صاحب نے تو کوئی بداخلاقی نہیں کی۔ ہاں، علمی اختلاف کیا ہے، بھلے اس کی بنیاد خود رائی ہی کیوں نہ ہو اور ا ن کا انداز ادعائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جواب کیا آ رہا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر جناب انعام صاحب اپنے کو ’’علامہ‘‘ سمجھتے ہیں تو اس پر جناب رشید صاحب کا اعتراض اس وقت قابل فہم ہو سکتا تھا اگر وہ آج کل ’’مولانا‘‘ بننے کے معیارات کا جائزہ بھی تھوڑی سی دیانت سے لکھ دیتے۔
یہ تو بے چارے اس آدمی کا حشر ہوا جس نے خود کو پروفیسر کہنے کی جسارت کر لی۔ مجھے تو مدیر صاحب! آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے، بلکہ محبت میں تو اکثر یہ کہہ جاتا ہوں کہ ’’میں عمار ناصر خان کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں‘‘ جب مذہبی طبقے اور مولانا حضرات کے تبصرے آپ کے بارے میں سنتا ہوں۔ ہمارے مذہبی طبقے کو اب کوئی نوشتہ دیوار بھی نظر نہیں آتا۔ خدا خیر کرے!
محمد دین جوہر، صادق آباد
پرامن اور متوازن معاشرے کے قیام میں علماء کا کردار
ادارہ
(۲۲، ۲۳ جون ۲۰۱۱ء کو پاک انسٹی ٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار میں اہل علم ودانش کی گفتگو کے منتخب اقتباسات۔)
مولانا محمد خان شیرانی
(چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان )
آج حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جب دنیا عقل اور دلیل کی بات کرتی ہے، وہاں پر ہم جو ان اداروں کے تعلیم یافتہ ہیں، فتویٰ کی بات کرتے ہیں، حالانکہ فتویٰ اور دلیل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ .... تمام علماء کرام کو معلوم ہے کہ نبوت کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی انسان معصوم نہیں کہلا سکتا کہ اس کی کسی بھی رائے میں کوئی جھول نہ ہو۔ اور نبی ہی وہ شخصیت ہوتی ہے جو معصوم اور واجب الاطاعت ہے۔ آج کے زمانے میں اگرکوئی بہت بڑا عالم ہو گا تو وہ مجتہد بنے گا اور مجتہد مصیب بھی ہوسکتا ہے اور مخطی بھی اور وہ واجب الاطاعت نہیں ہے۔ ہر مجتہد کا اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اجتہاد کو تحمیل کرنا اس کا حق نہیں۔ اس حوالے سے قانونِ فقہ میں دو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی عمل سر زد ہو جائے اور اس عمل کے لیے قرآن و سنت میں نصِ صریح موجود نہ ہو تو پھر اس حکم کی تلاش کے لیے جو عمل کیا جاتاہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ...... ایک اجتہاد کسی دوسرے اجتہادکا راستہ نہیں روک سکتا ۔یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس حکم کی تلاش میں ہوں، آپ سب آرام کرو اور نہ کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کو دوسروں پر تحمیل کر سکتا ہے۔ دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی اس کا قائل ہو گا تو ساتھ دے گا، قائل نہیں ہو گا توساتھ نہیں دے گا۔ ...... لہٰذانہ کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کو تحمیل کر سکتا ہے اور نہ کوئی متحری اپنے تجربہ کوتحمیل کر سکتا ہے۔ جب یہ پتہ ہو تو پھر اجتہاد عمل کے لیے ہوگا اوراگر علم کو عمل کے لیے حاصل کیا جائے تو عمل کے میدان میں جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا تحمیل میں آتا ہے ،جب ہر عالم اپنے علم کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہے جوکہ علم اور نہ ہی مذہب کا تقاضا ہے۔
ڈاکٹر خالد ظہیر
(ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب، لاہور)
ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو نہ امریکہ، نہ اسرائیل اور نہ بھارت چلا رہا ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اغیار ہمارے خلاف سازش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ درست بات یہ ہے کہ ہم اپنی تباہی و بربادی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کاخالق و مالک ہے۔ وہ کسی امریکہ یا کسی اسرائیل کو قطعاً یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کائنات کی تباہی و بربادی کی خواہش کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوسکتا کہ ایک جانب اس کے ماننے والے پر خلوص طریقے سے اس کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور دوسری جانب کچھ مخالفین سازشیں کریں اور پھر وہ ان سازشوں میں کامیاب بھی ہو جائیں۔آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے نزول سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھی اور وہ اللہ کی کتاب اوراس کے پیغام کے حامل تھے۔ ان کی اخلاقی و دینی گمراہی کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے: ’’ ہم نے تم پر مسلط کیے اپنے بندے، انہوں نے تمہارے گھر تہس نہس کر دیے،تمہارے شہروں کو برباد کر دیا۔‘‘ اس وجہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ میں سب سے زیادہ فکر مند اس بات پر ہوں کہ ہم میں وہ کیاخرابیاں اور کیاکمزوریاں درآئی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے اور ہم اس کی تائید اور نصرت سے محروم ہو گئے ہیں اور اغیار کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ ......
پرامن اور متوازن معاشرے کے قیام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جمعہ کے خطبے، امامت اور مسجد کے بارے میں اس سنت کو زندہ کریں کہ ان کا انتظام مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہو۔ جمعہ کا خطبہ حکمران دیں اور وہی امامت کروائیں اور ممکن ہو تو بقیہ نمازوں کی بھی امامت کروائیں۔ حکمران جہاں مناسب چاہیں، اپنی نیابت میں علما کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کے اس خوبصورت طریقے کے اجرا کے نتیجے میں ایک جانب حکمرانوں کا دین اور مسجد سے تعلق قائم ہوگا اور عوام الناس کے سامنے مستقل جوابدہی کی خوبی پیدا ہو گی تو دوسری جانب جمعہ کے خطبات اور مسجدیں فرقہ وارانہ جھگڑوں کا پلیٹ فارم بننے سے آزاد ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے معاشرے سے غیر متوازن سوچ ختم ہو جائے گی۔ اس تبدیلی کا بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ حکومت کے فیصلے کے نتیجے میں علما کی مسجد میں تعیناتی ان کو مسجد کمیٹی کے اثرو رسوخ سے آزاد کروا کے حکومت کا ملازم بنادے گی اور وہ حکومت کے ملازمین کی مراعات کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ مسجدوں میں علما کو یہ موقع ملے گا کہ وہ حکومت کی مرضی کے مطابق نماز کے اوقات کا تعین کریں اور عوام الناس کو دین کی تعلیم دیں۔مساجد کے معاملے میں اس اسلامی طریقے سے متوازن سوچ خود بخود پروان چڑھے گی۔ مسجدیں کبھی فرقہ واریت کے لیے استعمال نہیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی گروہ عام آدمی کو دین کے نام پر تشدد اوربدامنی کی طرف ابھار سکے گا ۔علما کو اس تبدیلی کے برپا کرنے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی زبان سے دین کا یہ اہم تقاضا مطالبہ کی صورت میں سامنے آئے گا تو اس کے پورے ہونے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔.....
میں نے جب اپنا یہ نقطہ نظر کسی اور پلیٹ فارم پر پیش کیا تو مجھے ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ جب آپ حکمرانوں کو خطبہ اور امامت کا حق دیتے ہیں اور اگر حکمران کوئی خاتون ہو توپھر کیا ہو گا؟ میں نے کہا، اگر ہمارے ہاں یہ قانون بن جائے اور اس کے بعد مسلمان جانتے بھی ہوں کہ مسلمانوں کا حکمران امامت بھی کرتا ہے اور خطبہ بھی دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان ایک عورت کو حکمران کیونکر بنائیں گے! پہلے مسلمانوں کی تربیت کی جائے کہ وہ اپنے دین کو سمجھیں اور اس کی غیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر آپ اور میں اصولی طور پر متفق ہوں کہ ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے میں ایسا ہی ہونا چاہیے تو ہم اپنے اس دینی فہم کو بغیر کسی رکاوٹ کے بیان کریں۔ ہاں آپ کا اور میرا نفاذ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں حکمرانوں میں بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔اگرآپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے تو اس پرالگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہم دین کے اصول کو اصول کے طور پر بیان کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح ہم آئیڈیل کی طرف جائیں گے تو پھر اس کے نفاذ پر گفتگو ہوگی۔....
مولانا قاری محمد حنیف جالندھری
(جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ پاکستان)
علاقا،ئی ملکی اور گھر کے معاملات میں جب تک ہماری پالیسیاں دوغلی ہوں گی تو ہم ایک متوازن اور مثالی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے۔ اگر میں اپنے مسائل کو اپنے مسلک کی نگاہ سے دیکھوں گا تو میں کبھی اپنے مسائل حل نہیں کر سکوں گا۔ میرے مسلک کا کوئی بندہ خواہ وہ کوئی غلط بات کرے، میں اس کی تاویل کروں اور دوسرے مسلک کا کوئی بندہ صحیح بات بھی کرے تو میں تردید کردوں، جب تک ہمارے تاویل و تردید کے پیمانے حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوں گے اورہم مسلک کی بنیاد سے بالاتر نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر سکتے۔ ہم جب تک اپنے آپ کو فریق کی نظر سے دیکھیں گے تو ہم اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ جس دن ہم عملی طور پر ایک دوسرے کے رفیق بننے کا فیصلہ کرلیں گے تو اس وقت ہم پرامن اور متوازن معاشرہ قائم کرلیں گے۔......
ہم سب علماء بارہابیع فاسد پڑھتے پڑھاتے ہیں ۔ خریدوفروخت کے کتنے ہی معاملات ہیں جن کو شریعت ناجائز قرار دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جس سے کل عاقدین میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے ایسی خریدوفروخت اور لین دین بھی نہ کرو جو تمہارے درمیان نزاع کا سبب بن جائے۔ ..... مثال کے طور پر ایک فریق کہتا ہے کہ یہ چیز تم مجھے اب دے دو ،میں پیسے تمہیں بعد میں دوں گا اور یہ نہیں بتاتا کہ کس دن دے گا تو یہ جہالت جو ادائیگی ثمن کی ہے، کل کو جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے۔ بعدازاں وہ کہے گا کہ پھر دے دینے سے میری مراد کل یا پرسوں دے دیناوغیرہ تھی، جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ میری مراد تو ایک سال تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جب میری گندم آئے گی،تب دوں گا تو اسلام ایسی شرط جو فریقین کے درمیان جھگڑے کا سبب بنے، اس ذریعے کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اس طرح اسلام میں حقوق وفرائض کا جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق دینے کا خیال کرو، حقوق لینے کا خیال نہ کرو۔ جبکہ آج کی دنیا کے فکر اور فلسفے کہتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق پورے کرو نہ کرو، اپنے حقوق کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ علما کے منبرومحراب کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے اور پھر جب ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء تو انسان کو اللہ سے اور انسان کو انسان سے ملانے کے لیے آتے ہیں اور وہ ایسا انسانی رشتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں تو علما کی ذمہ داری بھی انسان کو اللہ سے اور انسان کو انسان سے ملانے کی ہے،توڑنے کی نہیں بلکہ جوڑنے کی ہے۔
ڈاکٹر قبلہ ایاز
(ڈائریکٹر شیخ زاید اسلامک سنٹر، پشاور)
اس وقت دنیا میں دو لابیاں فعال ہیں، ایک پیس لابی اور دوسری وارلابی ۔ وار لابی افغانستان میں بھی ہے اور خیبرپختونخوا و قبائلی علاقوں میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ اور یورپ میں بھی۔جبکہ اسی طرح پیس لابی بھی دنیا کے تمام خطوں میں موجود ہے ۔اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں وار لابی کا حصہ بننا ہے یا پیس لابی کا۔ وار لابی وہ ہے جو اس خطے میں جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے اور پیس لابی وہ ہے جو اس مسئلے کا حل چاہتی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اوباما پیس لابی کا جبکہ امریکی فوج وار لابی کا حصہ ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے۔ اوباما کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان سے نکلا جائے، چنانچہ پیس لابی وہاں بھی موجود ہے۔ ہمارے یہاں بھی وار لابی اور پیس لابی فعال ہے۔ جنگ کی بہت بڑی معیشت ہے جس کا حجم اربوں کھربوں روپے ہے جس سے امریکہ میں بھی لوگ کما رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور افغانستان میں بھی معاشی فوائد حاصل کررہے ہیں۔جب تک وار لابی معاشی ثمرات حاصل کرتی رہے گی، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو۔ علمائے کرام اور ہمارا دینی طبقہ لاشعوری طور پر وار لابی کے اہداف کا شکار بن جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیس لابی کا حصہ بن جائیں۔ علمائے کرام کے اندر اس قدر استطاعت ہے کہ اگر وہ پیس لابی کا حصہ بن جائیں تو افغانستان کی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔
خطے کی موجودہ صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علمائے کرام کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ طالبان کو سمجھائیں۔ خیبرپختونخوا میں کچھ ایسے علما ہیں جو طالبان کو سمجھا سکتے ہیں کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے تناظر میں افغانستان میں آپ نے قومی مفاہمت کی حکومت بنانی ہے اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں جن کا افغانستان کی سرزمین سے تعلق ہو۔ یہ چیز اسلام کے آئین کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ یہ حقائق کی دنیا ہے، خواہشات کی دنیا نہیں کہ اب ایسا ممکن نہیں کہ افغانستان میں جو دیگر فریق ہیں، آپ انہیں افغانستان کی سیاست سے بے دخل کرکے حکومت بنائیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل مذاکرات کے ذریعے نہ ہو اور اگر مذاکرات کے ذریعے حل نہ ہوا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورا خطہ امریکہ کے نکلنے کے بعد خانہ جنگی کی صورت اختیار کر جائے گا اور خون کا ایک بہت بڑا دریا اس خطے میں بہے گا، لیکن اگر مذاکراتی عمل کے نتیجے میں اس کا حل نکل آئے جس کی ایک صورت موجود ہے اور علمائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ آگے آئیں اوراپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ افغانستان کا بعد از امریکہ کیا حل ممکن ہوسکتا ہے۔ ......
خو اہشات کی دنیا مختلف ہے، لیکن حقا ئق مختلف ہیں ، مثلا جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم کا فیصلہ بھی مذاکرات پر ہی ہو ااور افغانستا ن کا مسئلہ بھی میز پر ہی حل ہونا ہے۔ اگر یہ طے نہیں ہو ا تو اس علا قے کے سیاسی طا لب علم کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہو ں کہ بہت بڑا نقصان ہو گا۔ ان حالات میں دو طرح کے گروہ فعال ہیں۔ ایک گروہ چا ہتا ہے کہ امریکہ کو اسی طر ح سے بھگا دیا جا ئے جیسا کہ روس کو بھگایا گیا تھا اور دوسرا گر وپ یہ کہتا ہے کہ مذاکراتی عمل کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا ئے۔ اب ظا ہر ہے کہ مذ اکرات کے لیے کسی نہ کسی کو درمیان میں آ نا ہے اور ہم اقوام متحدہ سے لا کھ شکایت کر یں، لیکن جس طر ح میں نے گزارش کی کہ حقا ئق کی دنیا الگ ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا بین الاقوامی معاملہ طے کرنا ہو تو وہ اقوام متحدہ کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ امر یکہ اس میں خفت اور سبکی محسوس کرے گا، لیکن اگر اقوا م متحدہ ایک نمائندہ منتخب کرے جس طر ح کسی زما نے میں روس کے مسئلے کے حل کے لیے اقوامِ متحدہ کے نمائندے آتے رہے ہیں۔ میں نے تجو یز پیش کی تھی کہ اگر اس نمائندے کا تعلق تر کی یا ملا ئیشیا سے ہو تو وہ زیا دہ مفیدثابت ہو گا کیونکہ تر کی پر طا لبا ن کا بھی اعتما د ہے اور ترکی نیٹو کا حصہ بھی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کو بھی تر کی پر بہت اعتما د ہے۔ اب خیبرپختونخوا اور فاٹا میں کچھ ایسے علما ہیں جو طا لبا ن کے ساتھ مذ اکر ات کر سکتے ہیں اور وہ طا لبا ن کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ مذاکراتی عمل کے ذریعے اپنی مزاحمت کو جاری رکھیں، کیونکہ جب تک افغانستا ن میں تما م فریقوں کو نمائندگی نہیں دی جاتی اور قومی مفا ہمت کی حکو مت قائم نہیں ہوتی توعالمی سطح پر اس طر ح کی حکو مت کو قبو ل نہیں کیا جائے گا۔ ....
معا شرتی علو م میں آپ نے قرائن کو دیکھنا ہو تا ہے اور معاشرے کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے اوریہ دیکھنا ہوتا ہے کہ معاشرے کس طر ح چلتے ہیں۔ امریکی معاشرہ اور سماج کس طر ح چلتا ہے ، اس حوالے سے امر یکہ میں لا بنگ کا بڑ ا اہم کردار ہے۔ جس طرح ہم یہاں ایم پی اے یا ایم این اے کو رشوت دیتے ہیں، اسی طر ح کی رشوت ادھر بھی ہو تی ہے لیکن اس کو رشوت نہیں، لا بنگ کہا جا تا ہے۔ مثلا ہم جنس پرستوں کی لابی ہے۔ ہم جنس پر ستوں کی لابنگ ایک بڑا گروپ’ کا کس‘ کرتاہے۔ امریکہ میں ایک نظام قائم ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ امریکہ کی فو ج پا کستان کی طر ح ہے۔ میں آپ کو بتاؤ ں کہ کسی حد تک ایسا ہی ہے اوروہاں پر فو ج کے اپنے مفاد ات ہیں جو کہ وار لابی کی ہم نوا ہے۔اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سکیورٹی گیٹس جو کبھی صدر اور وزیر اعظم کے لیے استعمال ہوتے تھے، اب ہر جگہ ان کو نصب کیا جاتا ہیں۔ ان سکیورٹی گیٹس کی فروخت سے حاصل ہونے والا منا فع وار لا بی کو جا تا ہے۔ وار لا بی یہ سکیورٹی گیٹس فروخت کرتی ہے۔
اسی طرح وار لا بی قبا ئل میں بھی کا م کر تی ہے۔ وہاں ہونے والی اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے پس پردہ وار لابی ملوث ہوتی ہے، جیسا کہ ہما ر ے ایک وائس چا نسلرکو اغوا کیا گیا اور انہیں دس کر وڑ تاوان ادا کرکے رہا کروایا گیا۔ وار لابی کی طرح جنگی معیشت (وار اکانومی) بھی ہے جو اپنا کا م کر تی ہے۔ افغا نستا ن میں واراکانومی ہے اور افیون کی کا شت کا معا وضہ حا مد کر زئی کا بھا ئی وصول کرتا ہے۔ اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ جنگ جا ری رہے۔ دنیا میں ایک بہت بڑی وار لا بی کا م کر رہی ہے، بد قسمتی سے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کر نا ہے کہ ہمیں وار لا بی کا ساتھ دینا ہے یا پیس لا بی کا۔ اور پیس لا بی کا حصہ بننا بہت مشکل کا م ہے اور وار لابی کا حصہ بننا بہت آ سا ن ۔وار لابی کا حصہ بن کر آپ ہیر و بھی بن جا تے ہیں اور آپ کا بڑا استقبال بھی ہو تا ہے اورآ پ کو پھو ل بھی پہنا ئے جا تے ہیں ، لیکن پیس لا بی کا حصہ بننے سے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ ہما ری عورتیں بیو ہ بن رہی ہیں اور نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پیس لا بی کا حصہ بنیں۔
مولانا محمد یٰسین ظفر
(ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان)
دعوتِ دین کے لیے پرامن ماحول ہی سازگار ہوتا ہے۔ جس قدر امن ہوگا، اتنی ہی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز کیا تو کفار کا جیسا بھی رویہ رہا، مگر آپ نے امن کے لیے ہی اپنی جدوجہد جاری رکھی اور کبھی بدامنی پیدا نہیں ہونے دی۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کو بھی اسی لئے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’اس رب کے گھر کی عبادت کروجو بھوک سے تمہیں کھلاتا ہے اور خوف سے امن دلاتا ہے‘‘۔
خوف ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس میں انسان کچھ بھی نہیں کرپاتا۔ گھبراہٹ اور خوف میں وہ کوئی بھی خطرناک قسم کا قدم اٹھا سکتا ہے، لہٰذا دعوت تبلیغ میں انبیا اور علما کے کردار کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں جانا پسند فرمالیا تھا، لیکن مکہ کا ماحول خراب نہیں ہونے دیا ۔اسی طرح آپ نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، لیکن مکہ میں بدامنی پیدا نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔اس لیے کہ خیر کے تمام سرچشمے امن سے پھوٹتے ہیں۔ کوئی بھی زندگی ہو، وہ امن سے ہے اور امن ہے تو زندگی ہے۔ اگر امن ہے تو خوشحالی ہے اوردعوت و تبلیغ بھی ممکن ہے ۔سیرت نبوی اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کافروغ اور دعوت و تبلیغ حالتِ امن میں ہی ہوئی، نہ کہ جنگ و جدل اور فساد کے حالات میں ممکن ہوئی۔
میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں سے ایک صلح حدیبیہ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جو ۶ ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر صلح حدیبیہ تک امن کے لیے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں۔ جنگ و جدل بھی ہو ا، لیکن اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے اور پھر جب آپ نے صلح حدیبیہ میں کفار سے دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تو مسلمانوں کو امن و سکون میسر آیا۔ پھر آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ امن کے ماحول کے باعث لوگوں کو موقع ملا کہ وہ اسلام پر غور و فکر کر سکیں۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ دو سال بعد جب مکہ والوں نے معاہدے کو ختم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے ۔ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثارصرف پندرہ سو تھے، لیکن دو سالوں بعد جب آپ دوبارہ مکہ تشریف لے گئے تو یہ تعداد دس ہزار تک پہنچ جاتی ہے، یعنی دو برسوں میں مسلمانوں کی تعداد میں جتنا اضافہ ہوا،وہ سترہ سالوں میں نہیں ہو سکا۔
امن کی کیفیت میں جو کام ہوتا ہے، وہ سکون و اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب افریقہ کی فتح ہوئی تو ایک بربری قبیلہ جو مسلمانوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا،بلکہ ہمیشہ برسرِ پیکار رہتا تو اس وقت مصر کے گورنر عبدالعزیز بن عبدالملک نے موسیٰ کو اس علاقے کا عامل اور لشکر کا امیر مقرر کر دیا۔ انہوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ پہلے ان علاقوں میں امن قائم کیا اور پھر داعی اور مبلغین کو وہاں بھیجا جنہوں نے وہاں جاکر لوگوں کو اسلام کی دعوت سے روشناس کیا اور اسلام کی تہذیب سے آگاہ کیا ور امن کے چند مہینوں میں بہت سے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور وہی بربری قبائل جو مسلمانوں کے مقابل تھے، اب ان کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ اسی طرح انڈونیشیا اور ملائشیا میں اسلام جنگ و جدل کے ذریعے نہیں پہنچا بلکہ وہاں تاجر اور علما پرامن ماحول میں گئے اور اسلام کی تعلیمات کو پیش کیااور یہ تمام لوگ حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے ۔میرا استدلال صرف اتنا ہے کہ امن کے ماحول میں جتناکام ہو سکتا ہے، وہ کسی اور حالت میں نہیں ہوسکتا ۔علما کا بنیادی کام دعوت و تبلیغ ہے، اس لیے ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن کے ماحول کو سازگار بنائیں اور بدامنی کا خاتمہ کریں اور امن کو فروغ دے کر اپنی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچائیں۔
ڈاکٹر أبوالحسن شاہ
(دار العلوم غوثیہ محمدیہ، بھیرہ شریف)
پرامن معاشرے کے قیام کی راہ میں حائل وہ رکاوٹیں جو مذہبی نوعیت کی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے علمائے کرام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ مسلک کی تقسیم کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی کی جو فضا پیدا ہوتی ہے، اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ علمائے کرام دوسرے مسالک کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر مسلک نے اپنے افکار و نظریات پر ہی قائم رہنا ہے، لیکن دوسرے مسلک کے ساتھ لاکھ اختلافات کے باوجود یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کاو جود ایک حقیقت ہے۔ اس حوالے سے بدامنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تقریر و تحریر میں بے اعتدالی قائم ہو جائے ۔ تکفیر اور قتل کے فتوؤں کی نوعیت بہت ہی سنگین ہے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور دوسرے مکاتبِ فکر کے اکابرین کو برا بھلا کہنے سے بھی بدامنی جنم لیتی ہے۔ اس کے خاتمے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مسلک اپنے سچا ہونے کی دلیل اس کو نہ سمجھے کہ دوسروں کا اس کے نقطۂ نظر سے متفق ہونا ضروری ہے ۔پہلی چیز تو یہ ہے کہ تحریرو تقریر میں اعتد ال اور احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ پرامن معاشرے کا قیام ممکن ہوسکے ۔مسلک کی تقسیم کی وجہ سے بدامنی کی صورت قائم ہونے کا دوسرا سبب طریقۂ تدریس و تقریر ہے۔ ہر مسلک کا مدرس و خطیب اپنی تقریر و تحریر میں طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرتا ہے کہ و ہی سچا ہے،باقی سب جھوٹے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس طرزِ عمل سے معاشرے میں نفرت جنم لیتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ اور سامعین کے ساتھ ساتھ علماء کرام اپنے ذہنی افق کو وسعت دیں۔
قرآن و سنت کے دلائل کو اپنے مسلک کے مطابق کرنے کی بجائے اپنے مسلک کو قرآن و سنت کے تابع اور طلبا و سامعین کواختلاف رائے برداشت کرنے کا خوگر بنایا جائے۔ سامعین سے میری مراد مساجد میں خطبا کی تقاریر سننے والے لوگ ہیں۔یہ خطبا اپنے سامعین کو بتائیں کہ اختلاف رائے ہر جگہ ممکن ہے ،لیکن جارحیت پر اتر آنا مستحسن نہیں۔ اسی طرح علمائے کرام مسلک کی تعلیم دینے کی بجائے دین اسلام کی تعلیم کو عام کریں۔ اگر ان باتوں پر اختلاف رائے کیا جائے جو کہ ضروریات دین میں سے ہیں ،جیسا کہ ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہؓ، احترام اہل بیت و صالحین، تو معاشرے سے بدامنی کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ بزرگانِ دین کے بارے میں نازیبا کلمات کسی صورت میں برداشت نہیں ہوسکتے ، لہٰذاامن کے قیام کے لیے ان ہستیوں کا احترام ضروری ہے۔
مولانا عمار خان ناصر
(ڈپٹی ڈائریکٹر الشریعہ اکادمی، گوجرانوالہ)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور لوگوں کے اخلاق و کردار کو بہتربنانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امن کا قیام اور وہ عناصر جن کے درمیان روایتی پس منظر میں تصادم کی صورتیں موجود تھیں یا جہاں معاشرے میں تصادم اور خون ریزی کا خطرہ موجود تھا، تو یہ صورت حال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا موضوع تھا۔ خاص طور پر مدینہ طیبہ میں اس کے تین اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خو داپنی ذاتِ گرامی کو اس حوالے سے بہترین نمونے کے طور پر پیش کیا کہ آپ کی ذاتِ گرامی سے ایسی کوئی بات صادر نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو، دکھ ہو یا اس سے ایسا اشتعال پیدا ہو جو معاشرے کا امن خراب کرنے کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچائی، نہ زبان سے اور نہ ہی ہاتھ سے۔ جن لوگوں نے حضور کو اذیت پہنچائی توآپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ کو ایک ریاست کے حاکم کی حیثیت حاصل ہوئی تو آپ نے بہت سے مواقع پر جب منافقین یہود و نصاریٰ نے آپ کی ذات کو طعن و تشنیع اور توہین کا نشانہ بنایا، تو آپ نے اس طرح کے واقعات سے صرفِ نظر کیا اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا تاکہ بات آگے بڑھ کر تصادم کی شکل اختیار نہ کرے۔ اس طرح کے واقعات سیرتِ طیبہ میں معروف ہیں۔ علما منصب نبوت کے وارث ہیں۔ اگرچہ انہیں نبوت منتقل نہیں ہوئی، لیکن نبوت کے منصب کی جو شان ہے، یعنی اس کے جو روحانی اور دعوتی پہلو ہیں،وہ یقیناًمنتقل ہوئے ہیں۔ علمائے کرام بھی اپنے شخصی کردار سے اس کا نمونہ پیش کریں، تاکہ ان کی ذات معاشرے اور ماحول میں امن کا پیغام پھیلانے کا ذریعہ بنے ۔ان سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جس سے معاشرے میں امن خراب ہو۔
دوسری چیز جو سیرت نبوی میں نمایاں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو بھی تنازعات اور مسائل موجود تھے، آپ نے انہیں حل کرنے کی کوشش کو اپنا مقصد بنایا۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اردگرد جو مختلف قبائل تھے، وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے ان قبائل میں جانے کا سبب یہ بیان کیا جاتاہے کہ آپ ان قبائل میں مختلف خاندانوں کے آپس کے تنازعات کا تصفیہ کرواتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ آپ کے پاس قانونی اختیار بھی تھا اور آپ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اس موقع پر آپ نے جو غیر معمولی اعلانات اور فیصلے کیے، ان میں سے ایک تاریخی نوعیت کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ آپ نے عرب قبائل میں چلے آرہے تنازعات کا خاتمہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ماضی کے قصاص کے کسی مقدمے کو زیربحث نہیں لایا جائے گا۔
تیسری اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے کے جن عناصرکے مابین مختلف جگہوں پر تصادم کا امکان موجود تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی پوری نظر رکھی اور اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے تشریف لے جانے سے پہلے لوگوں کو ان مقامات کے حوالے سے آگاہ کردیں کہ میرے جانے کے بعد یہاں یہ صورتحال پیدا ہوگی اور اس میں تم نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ حدیث میں تین بڑی معروف مثالیں ہیں ۔ پہلی یہ کہ آپ کو احساس تھاکہ میرے بعد حکمرانی کے حوالے سے انصار اور مہاجرین میں کشمکش کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو موضوع بنایا اور انصار کی ذہن سازی کی اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تمہاری بڑی قربانیاں اور خدمات ہیں، لیکن پورے عرب پر حکومت کرنے کے لیے قریش ہی زیادہ موزوں ہیں، چنانچہ تمہیں نظر انداز کیا جائے گا اور تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تمہیں اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ پھرآپ نے حکمرانوں کی طرف سے ظلم و زیادتی اور اس کے ردِعمل میں لوگوں میں جو اشتعال پیدا ہوسکتا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد لازماً ایسے حکمران آئیں گے جو ظلم و ستم روا رکھیں گے اور ناانصافی کریں گے۔ آپ نے عوام کو بہت واضح ہدایات دیں کہ جب تک حکمران کفر بواح کے درجے پر جا کر کسی حرکت کا ارتکاب نہ کریں تو تمہیں ان کا ظلم برداشت کرنا ہے اور ان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت نہیں کرنی اورتم نے ہر حال میں حق گوئی کرنی ہے۔ تیسری چیزیہ کہ عرب قبائل میں جوکشمکش چلی آرہی تھی، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو بھی عنوان بنایا اور فرمایا کہ ’’یہ نہ ہو کہ میرے بعد تم دوبارہ اس کفر کی حالت میں چلے جاؤ جس میں لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے۔‘‘
یہ تین پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سامنے آتے ہیں۔ علما کا بھی یہ معیاری کردار بنتا ہے کہ معاشرے میں امن و امان کی بات کی جائے تو یہ مطلوب بھی ہے اور ان سے اس کی بجا طور پر توقع بھی کی جانی چاہیے کہ وہ ان تین پہلوؤں سے اپنے معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اور فعال کردار ادا کریں۔ اس موضوع پر الگ بحث ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں طبقہ علما معروضی حالات میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتا اور وہ کیا وجوہ ہیں کہ علما کا طبقہ ایسے چند افراد سے، جن کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے، ان سے برأت کا اظہار کیوں نہیں کر رہا؟ یہ درست ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چند لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان سے خود کو الگ کرنے کی ذمہ داری علما پر عائد ہوتی ہے جو وہ پوری نہیں کر رہے اور ایک سطح ایسی بھی آتی ہے کہ اس طبقے کی نمائندگی کا شرف ہی اس محدود طبقے کو حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے سنجیدہ، باکردار اور مہذب لوگوں کو نمائندہ ہی نہیں سمجھاجاتا۔
مجھے میرے والد گرامی مولانا زاہد الراشدی نے یہ واقعہ سنایا کہ بچپن میں ان کے ہاں ایک جلسہ تھا تو والد صاحب، جن کی عمر اس وقت دس گیارہ سال تھی، کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو بھی تقریر کرنے کا موقع دیا گیا۔ہمارے دادا مولانا سرفراز خان صفدر بھی دوسرے علما کے ہمراہ وہاں تشریف فرما تھے۔والد گرامی بتاتے ہیں کہ میں نے قادیانیت کے موضوع پر تقریر کی تو غیرت ایمانی میں آکر مرزا غلام احمدقادیانی کو گالی دے دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا فوراً پیچھے سے اٹھ کر آئے اور انہوں نے مجھے گردن سے پکڑ کر پیچھے کیا اور میری جگہ پر کھڑے ہوگئے اور باقاعدہ معذرت کی اور کہا کہ یہ بچہ ہے اور نا سمجھ ہے۔ اس نے غلط بات کہہ دی ہے۔ اسے گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ میرے خیال میں جب تک یہ کردارہر طبقہ کے علما ادا نہیں کرتے، اس وقت تک یہ ذمہ داری درست طور پر ادا نہیں ہوسکتی ۔ جب تک ہم دیانت داری اور خلوصِ نیت کے ساتھ اس حوالے سے اقدامات نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم خود کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔
ڈاکٹر خالد مسعود
(سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان)
علمائے کرام کا کردار محض رہنما کا ہی نہیں، بلکہ دینی زندگی کی عملی مثال کے طور پر بھی ان کا کردار ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسلامی معاشرے کا ضمیر بھی ہیں ،چنانچہ یہ علما کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا نہ صرف جو اب دیں، بلکہ اس پربھی غور کریں کہ صورت حال کو اس نہج تک پہنچانے میں مذہبی طبقہ بلاواسطہ یا بالواسطہ کس حد تک ذمہ دار ہے۔ اگر ذمہ دار ہے تو اس کا حل کیاہے؟ ..... اس سلسلے میں خاص طورپر دو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری سیاسی، سماجی، معاشی فکر میں کچھ ابہامات موجود ہیں جنہیں دور نہ کیا گیا تو صورت حال خاصی حد تک اسی طرح رہے گی۔ یہ ابہامات تحریک پاکستان سے شروع ہوئے اور اب تک موجود ہیں۔ دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر توجہ نہ دی گئی تو بالواسطہ طور پر اس سے معاشرہ غلط رخ اختیارکرسکتاہے۔ سب سے پہلا مسئلہ قانون اور اس کی حکمرانی سے متعلق ہے۔ بہت ہی جسارت سے عرض کررہا ہوں کہ مذہبی طبقہ کی طرف سے سوالات پیدا کیے گئے جن کی وجہ سے لوگوں میں ابہام اور مشکل پیدا ہوئی۔ علما کا یہ کہنا ہے کہ وہ قانون جو حکومت بناتی ہے ، مذہبی حوالے سے اس قانون پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔کچھ قوانین واجب الاطاعت ہیں اور کچھ نہیں۔ علما کی جانب سے قانون کی اس تفریق سے لوگوں کے ذہنوں میں خلجان اور ابہام پیدا ہوتاہے اور جب تک ہم اس مسئلے کا واضح حل پیش نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ کافی ہے۔
دوسری چیز جو مذہبی طبقے سے منسوب کی جاتی ہے ، وہ مذہبی طبقے کی جانب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جس کے لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر کوئی خرابی ہے اور کوئی کام دین، شریعت یا فقہ کے خلاف ہورہا ہے تو اس پر از خود سزا دینا اور بغیر قانونی کارروائی کے ایکشن لینا کس حد تک درست ہے، اس حوالے سے مذہبی طبقے کو عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ملک میں معروف عدالتی نظام ہے، اس کے علاوہ جرگے، پنچایت اور دیگر سماجی ڈھانچوں میں فتویٰ نویسی بھی ایک عدالتی ڈھانچے کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ اس میں لوگ مختلف علمائے کرام اور مفتیان عظام سے رہنمائی چاہتے ہیں تو اس فتویٰ کی حیثیت بھی ایک فیصلے کی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ابہام پیدا ہوتے ہیں۔
دوسرا پہلو جس پر سماجی حوالے سے بہت بات ہوئی، وہ ہمارے معاشرے میں پنپنے والے عدم برداشت کے رویے ہیں جس پر بہت سے علما نے بات کی۔ میں کھل کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کے مدرسے توکسی مجبوری کی بنا پر کسی ایک مسلک سے منسلک تھے، لیکن مساجد بھی مختلف مسالک سے منسلک ہوئیں اور اس کی وجہ سے معاشرے میں دین و مذہب کے نام پر عدم برداشت کے رویے فروغ پائے۔ یہ بھی قابل غور ہے۔
سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے۔ معاشی مسائل میں جو عام رجحان ہے، وہ حکومت کی طرف سے عائد کردہ ٹیکس اور جو دینی ادائیگی ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ، ان میں فرق ہے کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو ٹیکس نہیں دینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علما نے اس بارے میں فتویٰ جاری کیا ہے لیکن عوام میں اس بارے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح رشوت کے بارے میں بھی ابہام ہے۔ مثال کے طور پر مختلف فتادیٰ میں ہے کہ اگر مجبوری میں کوئی جائز کام نکل نہ رہا ہو تو اس میں رشوت دیناجائز ہے تو اس سے بھی ایک طرح سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔جس وقت ہم جاگیرداروں اور زمین داروں کی بات کرتے ہیں تو علما کا قیامِ پاکستان سے پہلے عمومی رجحان یہ تھاکہ حکومت اگر معاشرے کی ضرورتوں کے لیے زرعی اصلاحات نافذکرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن جب پاکستان میں زرعی اصلاحات کی گئیں تو پھر شخصی ملکیت پر بھی ہمارے ہاں اختلافات پیدا ہوئے اوراس پر لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالیں اور بعض مواقع پر عدالتوں میں رجوع کرکے حکومت کو کہا گیا کہ یہ حکومت کے اختیار میں نہیں کہ وہ یہ ملکیت اپنے اختیار میں لے تو کبھی ہم شخصی ملکیت کو اس قدر فوقیت دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم وڈیروں، زمین داروں اور جاگیرداروں کے نظام کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔
تعلیمی مسائل پربھی بہت گفتگو ہوئی۔ اختلاف رائے ہماری روایات کاقابل فخر حصہ ہے۔ اختلاف رائے سے ہی بات آگے بڑھتی ہے اور ہمارے ہاں علما کے اختلاف کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے۔ہمارے مدارس میں پہلے تمام علما اور مذاہب کے کلامی اور فقہی اختلافات کو دلائل کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا اور اس کے بعد اپنے مسلک کی بات کی جاتی تھی، لیکن شاید اب نصاب کو مختصر کرتے ہوئے دلائل کا حصہ کم کر دیاگیا ہے، جس کی وجہ سے مسلکی اختلافات بڑھ گئے ہیں اوربعض اوقات ہم تعصب کی حد تک اپنے مسلک کے قائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ میں تحقیق کرنے اور آگے بڑھنے کار جحان نہ ہونے کے برابر ہے۔یہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں، ان میں کچھ میرے اپنے مشاہدات اور اندازے ہیں، جبکہ علما پرلکھی جانے والی کتابوں میں ان میں سے بھی بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سارے عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے۔
مولانا مفتی محمد زاہد
(شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ، فیصل آباد)
جہاں تک سنی مدارس ہیں، مثال کے طورپر بریلوی، اہل حدیث اوردیوبندی وغیرہ، ان میں دوسرے مکاتب فکر کی رائے کا ذکرہوتاہوگا اور دلائل بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ’ہدایہ‘ دیکھ لیں جس میں ائمہ أربعہ کے مؤقف دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ پیدا ہورہا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے تناظر میں جو مسالک ہیں، ان میں دوسرے کے مسلک کا درست تعارف نہیں کروایا جاتا۔ مثال کے طور میں ایک دیوبندی ہوں تو ایک بریلوی یا شیعہ کا میرے بارے میں تصور ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ ایک بریلوی کے بارے میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں۔ میرا تصور یہ ہے اور میں اپنے طالب علموں کو بھی ان کے بارے میں یہی بتاتا ہوں، لیکن حقیقت میں ان کا نقطہ نظر یہ نہ ہو۔ اہل تشیع ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں یہ بتاتے ہوں کہ ان کی اہل بیتؓ کے ساتھ وہ عقیدت نہیں جو ہونی چاہیے اور ہوسکتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اہل تشیع کے بارے میں یہ بتاتے ہوں کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے یا فلاں فرائض پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے یہ تاثر حقیقت کے خلاف ہو اور ان کے ہاں بھی یہ چیزیں نہ ہوں جس طرح ہم اپنے لوگوں کو ان سے متعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔
مشترکہ نصاب کی بات ہورہی تھی۔ اس کی تشکیل بہت زیادہ مشکل ہے،لیکن کوئی ایسا کتابچہ جس میں تمام مکاتب فکر کے بنیادی نظریات خود ان کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہوں، ہونا چاہیے اور وہ شامل نصاب کیا جاسکتا ہے، کیونکہ کسی بھی مکتبہ فکر کو اپنا عقیدہ بیان کرنے کا اختیار حاصل ہے اور وہ خود بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے ۔مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتحاد تنظیمات المدارس کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ ایسا کوئی مشترکہ مواد تیار ہو جائے جس میں تمام مکاتب فکر کی بنیادی چیزیں ہوں اور وہ بنیادی مسائل بھی زیربحث آجائیں جن پر ان مسالک کا اختلاف ہے تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا جاسکے۔ ایک دوسرے کے مکتبہ فکر کا تعارف اگر درست طور پر معلوم ہو جائے، اگرچہ دلائل نہ بھی ہوں تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔
مولانا مفتی منیب الرحمان
(چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی، صدر تنظیم المدارس پاکستان)
اس وقت ملک کاسب سے بڑا مسئلہ جس سے ہم دوچار ہیں، وہ عمودی اور افقی اور گہرائی اور گیرائی کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں نفوذ کرچکا ہے اور یہ بڑا گھمبیرمسئلہ ہے۔ اس کی مثال ایک ٹیومر یا کینسر کی نہیں کہ آپ ایک عضو کاٹ دیں اور اس کا علاج کر لیں تو جسم دوبارہ صحت مند ہوجائے گا۔ اس کی مثال شوگر، بلڈ پریشر اور بخار کی ہے جو کسی وقت بھی جسم کے کسی حصے کومتاثر کر سکتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اسی طرح یہاں اپنے آپ کو کوئی محفوظ تصور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ہمارے وہ حساس دفاعی ادارے بھی محفوظ نہیں جنہوں نے قوم کا دفاع کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہمہ گیر اور خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔
اس مسئلہ کے اسباب کودو طرح کے اندازِ فکر کے تحت زیرِبحث لایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ جس کا ابتدا میں ڈاکٹر فرید پراچہ نے ذکر کیا اور عالمی طاقتوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیاجن میں اسرائیل، انڈیا، امریکہ ، یورپ، یہود و ہنوداور استعمار شامل ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سرگرم ہیں اور ان عوامل کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہمیں آگ سے نکالنا ان کی ذمہ داری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی بقا و سالمیت کی ذمہ داری ہماری نہیں، کسی اور کی ہے جو کہ اپنا کام صحیح طو رپر نہیں کر رہا، لہٰذا اس کی مذمت اور ملامت کرو اور اس کے خلاف نعرے لگاؤ اور تحریک چلاؤ۔ میرے خیال میں پہلی اصابت رائے یہ ہے کہ ہم ادراک کریں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے اور اس کا امریکہ، یورپ اور یہود و ہنود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب تک ہم اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کا اعتراف نہیں کریں گے اور ان مسائل کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، کسی اور پر ذمہ داری ڈال کر ہم اپنے گھر کو نہ تو بچا سکتے ہیں اور نہ دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرا ہمیشہ سے یہ مؤقف رہا ہے کہ اگر ہم امریکہ یا یہود و ہنود کو جواب دینا چاہتے ہیں توہم اپنے ملک کو متحد ، پرامن اور منظم کرکے جواب دیں کہ یہ ہمارے مخالفین کی سازشیں تھیں اور ان کے تدارک کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے۔ حال ہی میں ترکی کی نشاۃِ ثانیہ ہمارے سامنے ایک بڑی مثال ہے۔ اس وقت ترکی کی کرنسی پچپن پاکستانی روپوں کے برابر ہے اور ترکی دنیا کی پندرہویں یا سترہویں بڑی معیشت ہے۔ وہاں امن و استحکام قائم ہوا ہے اور ترقی ہور ہی ہے۔ ہمیں بھی قوم کی نشاۃ اور استحکام کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر ہم نے دوسروں کو ذمہ دار قرار دینے کی روش برقرار رکھی تو پھر ہم اس پستی سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاں کئی طرح کے جبر ہیں، داخلی جبر ہیں جبکہ خارجی جبر تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ امریکہ یا کسی اور قوت کی ڈکٹیشن کا ذکر کرتے ہیں، داخلی جبر بھی بہت سارے ہیں، اور ہر مکتبۂ فکر کا اپنا بھی ایک جبر ہے۔ کوئی اس کو آسان نہ سمجھے۔ ہم پشاور میں ایک میٹنگ میں شریک تھے ، اُس وقت پشاور میں تواتر کے ساتھ خودکش حملے ہو رہے تھے تو میٹنگ میں ذکر آیا کہ خودکش حملوں کے بارے میں بھی بات کر لی جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آبا دمیں بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کرسکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پشاور میں بیٹھ کر ایسی کوئی بات نہیں کرسکتے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جب پشاور کے بازاروں میں دھماکے ہوتے ہیں تو کیا یہاں کے خطبا جمعہ کے خطبات میں ان کا ذکر کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بالکل ذکر نہیں کرتے، جیسا کہ یہاں سرے سے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی ذکر کرتا بھی ہے تو یہ کہے گا کہ امریکہ یہ کر رہا ہے یا بھارت یہ کر رہا ہے تو یہ بھی جبر کی ایک صورت ہے تو جب تک ہم اس جبر کا مل کر مقابلہ نہیں کریں گے اور اگر کوئی سچ کراچی میں نہ بولا جاسکے یا لاہور، اسلام آباد یا پشاور میں نہ بولا جاسکے تو جب تک ہم ہر جگہ سچ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے ، ہم کامل اصلاح نہیں کرسکتے۔ .....
ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس بات کو ایمان اور عقیدے کا درجہ بنا لیا ہے کہ چونکہ اب حکومت امریکہ کی غلام ہے ، لہٰذا اس ملک کے سارے ادارے، عوام، مارکیٹیں، بازار، مساجد اور مزارات، جس کو مرضی چاہیں نشانہ بنا دیں کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس سبب سے مارا گیا اور نہ مارنے والے کو۔ اس مسئلہ کو ہم سب مل کر اتفاق رائے سے حل کرسکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمام بڑے اور اکابر علما کو سامنے آنا ہوگا اور ایک سے زائد مرتبہ حجت شرعی کو تمام کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض لوگ حالات کے جبر کی وجہ سے یہ سیاسی بیان دیتے ہیں کہ ہاں یہ خود کش حملے حرام ہیں، یہ بات حرام ہے اور یہ بات حرام، مگر چونکہ یہ ڈرون حملے ہورہے ہیں اور چونکہ امریکہ یہ کررہا ہے اورحکمران یہ کروا رہے ہیں تو ردِعمل میں خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال بھی ہیں اور حرام بھی ۔ ان کے بارے میں ہمیں کھل کر بات کرنا ہوگی۔ ان کے بارے میں، میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، دیکھیں جی! یہاں بہت سے عناصرسرگرم ہیں اور باہر کی ایجنسیاں بھی فعال ہیں اور اس مقصد کے لیے باہر سے پیسہ بھی آ رہاہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ امریکہ، اسرائیل یا ہنود کروا رہے ہیں، وہ تو کفرہی پھیلائیں گے ،اسلام تو نہیں پھیلائیں گے۔ پھر ہمیں اس کے بارے میں دو ٹوک بات کرنے سے ایک لمحہ بھی اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اس کو مل کر عبور کرنے کی ضرورت ہے۔.....
میں کہنا چاہتا ہوں کہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی۔ مسالک بھی موجود تھے اور حتیٰ کے ایک دوسرے کے خلاف فتاویٰ تک بھی موجود تھے۔ کبھی کسی کو ددھکے دے دیے ،کسی کو تھپڑ مار دیا اور کبھی ایسا ہوا کہ لاٹھی کا استعمال کیا گیا ہو، لیکن اس وقت ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، وہ یہ ہے کہ دلیل اور استدلال کی طاقت کے استعمال کرنے کی بجائے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اسلحے کی طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلحے اور گولی نے دلیل کی جگہ لے لی اور یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ آپ مناظرے کریں، دلیل و استدلال سے کریں، دلیل سے اپنی بات لکھیں لیکن جب تک مذہبی طبقات میں اسلحہ موجود ہے اور ہم اس سے نجات حاصل نہیں کریں گے تو معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔
اہل مغرب اور امریکہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مدارس میں جو نصاب پڑھایا جارہا ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جو معاشرے میں بدمعاش، غنڈے اور دہشت گرد پیدا کرتا ہے۔ہم ان کو یہ بات باور کروا چکے ہیں کہ یہ نصاب دو سو سال سے پڑھایا جارہا ہے تودو سو سال سے بدمعاش اور دہشت گرد پیدا نہیں ہورہے تھے۔ تحریک پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد ہوئی۔اصل میں یہ جہادِ افغانستان کا تسلسل ہے ۔ہم اپنی خرابیوں کی ذمہ داری اوروں پر ڈال دیں گے، لیکن جب سوویت یونین کی فتح ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ ہماری فتح ہے۔ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں جو سرمایہ لگا ، وہ کسی اور کا تھا اور مقاصد بھی کسی اور کے تھے، لیکن ہم سارا کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔
اگر ہم نے اس ملک میں امن لانا ہے تو ملک کو اسلحے سے پاک کرنا ہوگا، بحث و مباحثے کے لیے دلیل کی زبان کو استعمال کیا جائے اور دلیل کا راستہ اختیار کیا جائے۔جس ٹریک پر ہم چل پڑے ہیں، اگر اس سے پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے تو ہمارے معاشرے میں سکون نہیں آسکتا۔ میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو طبقات اب تک مار کھا رہے ہیں اور جن کے پاس اس وقت اسلحے کی تکنیک و وسائل نہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو آخری چارۂ کار ہے، وہ یہی رہ جائے گا، لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے ۔ اس اسلحہ کوفروغ دینے میں اہل اقتدار کا بہت بڑا دخل ہے۔ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں اوران کے کلچر کو ہی اپناتے ہیں ۔ہم لوگ جو پرامن ہیں اور اپنے صاحب اقتدار لوگوں سے رجوع کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی جواب نہیں آئے گا، لیکن جو مسلح گروہ ہیں اور جن کے پاس اسلحہ ہے، انہیں فوراً رسپانس مل جائے گا اور ان کی بات بھی سنی جائے گی اور ان کو ملاقات کا وقت بھی دیاجائے گا ۔ہمارے حکمران بزدل ہیں اور بزدل لوگ امانتوں کی حفاظت نہیں کرسکتے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ایک طویل المدت قومی ایجنڈا بنایا جائے اور پوری قوم اس کی پشت پر کھڑی ہو اور اس ایجنڈے کو جماعتی، گروہی مفادات اور اپنے اقتدار کو طول دینے اور سیاسی مشہوری کا ذریعہ نہ بنایا جائے ،کیوں کہ اگر یہ ملک ہے تو یہ حکمران ہیں اور وہ ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے موجود ہوں گے اور اگر ملک نہیں ہوگا تو پھرکچھ نہیں رہے گا۔
سیمینار: ’’ائمہ وخطبا کی ذمہ داریاں اور مسائل ومشکلات‘‘
ادارہ
۱۶ رمضان المبارک کو الشریعہ اکیڈمی گوجرانوالہ میں ’’ائمہ وخطبا کی ذمہ داریاں اور ان کو درپیش مشکلات‘‘ کے عنوان سے ایک فکری نشست اکادمی کے ڈائریکٹر مولانا زاہد الراشدی کی صدارت میں منعقد ہوئی اور اس میں علاقے کے ائمہ مساجداور خطبا کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مولانا زاہد الراشدی نے کہا کہ ہم آج اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کریں گے، بلکہ ان ائمہ وخطبا کی بات ان کی زبانی سننا چاہیں گے، جو مختلف جامعات کے فضلا ہیں اور کسی نہ کسی مسجد میں امامت یا خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں کہ انہیں دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک مسجد میں امامت وخطابت کے فرائض سرانجام دیتے ہوئے کیامشکلات پیش آئی ہیں اور ان کے ذہن میں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ چنانچہ مختلف حضرات نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا، اس کا خلاصہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
جامعہ نصرۃ العلوم کے فاضل مولانا محمد اویس نے کہا کہ مدارس کے فضلاء کو سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ مسجدیا مدرسے میں دی جانے والی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ مثلاً چھ سات ہزار روپے میں اپنا خرچہ، گھر کا خرچہ، مکان کا کرایہ، بجلی وگیس کا بل اور دیگر ضروری اخراجات کسی طرح بھی پورے نہیں ہوتے، جس کے لیے انہیں متبادل ذرائع تلاش کرنا پڑتے ہیں اور وہ بطورخطیب وامام یا مدرس اپنے فرائض دل جمعی کے ساتھ سرانجام نہیں دے سکتے، جبکہ ان کے لیے دوسری بڑی الجھن یہ ہوتی ہے کہ انہیں مدرسہ ومسجد میں اپنی ملازمت کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا اور مہتمم صاحب یا کمیٹی کے رحم وکرم پر ہوتے ہیں، جو کسی بھی وقت ان کی چھٹی کراسکتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ دینی مدارس میں طلبہ کو عصری تعلیم دی جائے یا کوئی ہنر ضرور سکھایا جائے تاکہ وہ معاشی مشکلات پر کسی حد تک قابو پاسکیں۔ جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے فاضل مولانا عبدالوحید صاحب نے کہا کہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اربابِ مدارس فضلا کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، مدارس کی بلڈنگیں تو شایان شان بن جاتی ہیں، مگر مدرسین کی تنخواہوں اور دیگر سہولیات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔
جامعہ فاروقیہ کراچی کے فاضل مولانا ابوبکر نے کہا کہ دینی مدارس میں ہمیں جو تربیت ہوتی ہے، وہ بہت عمدہ اور بہترین ہوتی ہے، جس کا احساس ہمیں اسکولوں اور دیگر اداروں میں جاکر ہوتا ہے۔ ہمیں صبر، برداشت، توکل اور قناعت کی تعلیم ملتی ہے اور شرافت اور دین داری کا ذوق پیدا ہوتا ہے، البتہ معاشرے میں جاکر اپنے مسائل سے نمٹنے کے لیے دینی مدارس میں طلبہ کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھایا جائے تاکہ ان کا انحصار صرف مسجد کی تنخواہ اور کمیٹی کے رویے پر نہ ہو اور وہ متبادل ذریعہ معاش رکھنے کی وجہ سے آزادی اوروقار کے ساتھ دینی خدمات سرانجام دے سکیں۔
جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل مولانا محمد عامر نے کہا کہ ہمارے مدارس میں ابتداہی سے طلبہ کی ذہن سازی ہونی چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ انہیں معاشرے کی راہ نمائی کے لیے تیار کیا جارہا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق پڑھیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق ان کا ذہن ترقی کرتا چلا جائے۔ اسی طرح اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس معاشرے کا شایدصرف دو فیصد طبقہ آتا ہے، جبکہ باقی اٹھانوے فیصد کے لیے دینی تعلیم کا ہمارے ہاں کوئی منظم اور مربوط نظام موجود نہیں ہے، پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فاضل کسی اور شعبے میں چلاجاتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ دینی تقاضوں سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ ہمیں خود طلبہ کی ایک تعداد کو دوسرے شعبوں کے لیے تیار کرنا چاہیے اور پالیسی کے تحت انہیں وہاں بھیجنا چاہیے۔
مولانا منیراحمد نے کہاکہ مدارس کے فضلا میں سے ذی استعداد حضرات ہی مدارس میں تدریس کا منصب حاصل کرپاتے ہیں، جبکہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور دوسرے درجے کے فضلا جو کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، انہیں دوسرے شعبوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، جہاں ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں کام کرنے کے لیے نہ ان کے پاس وہاں کی بنیادی تعلیم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی تربیت ہوتی ہے، پھر ماحول مختلف ہونے اور وہاں کی تعلیم ضروری حد تک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسکولوں، کالجوں میں دوسرے درجے کا استاذ سمجھا جاتا ہے اور وہ بسااوقات احساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں، اس لیے اس کی منصوبہ بندی دینی مدارس کی تعلیم کے دوران ہی ہونی چاہیے کہ طلبہ کی جس اکثریت کو دوسرے شعبوں میں ہی جاناہے، انہیں وہاں کی بنیادی تعلیم اور وہاں کے ماحول سے آگاہی فراہم کی جائے اور انہیں اس کے لیے تیار کیا جائے۔
مولانا عاطف نے کہا کہ ہماری دینی جماعتوں کا شدت پسندانہ رویہ اور ایک دوسرے کی تحقیر وتنقیص بھی مساجد کے ماحول میں ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ مسجد کے نمازی اور کمیٹی کے ارکان اکثر بے علم ہوتے ہیں اور ان کے ردعمل کا شکار امام وخطیب کو بننا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ائمہ وخطباء کا آپس میں کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسا فورم موجود ہے کہ وہ جائز معاملات میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرسکیں، جس کی وجہ سے ہرمسجد کا امام وخطیب تنہائی کا شکار رہتا ہے اوراسے اپنے نمازیوں اور کمیٹی کے جائز یا ناجائز مطالبات سے خود ہی نمٹنا پڑتا ہے۔
جامعہ دارالعلوم کراچی کیفاضل مولانا حافظ محمد رشید نے کہا کہ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے فضلا میں سے ہر ایک کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں جاکر دین کی خدمت کرے گا لیکن عملی میدان میں جاکر اسے جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر شخص ان کا سامنا نہیں کرسکتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کی خدمت کرسکیں اور مسائل ومشکلات کا سامنا نہ کرپانے والے حضرات جب دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں تو انہیں بے دینی کے طعنوں کا شکار بنایا جاتا ہے، اس طرزعمل کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔
جامعہ نصرۃ العلوم کے فاضل مولانا وقاراحمد نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمودحسن دیوبندی نے تعلیمی میدان میں جس وسعت اور ہمہ گیری کا تصور دیا تھا، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں پورے معاشرے کو سمیٹنے کے حوالے سے ان بزرگوں کا جو وژن تھا، اسے دوبارہ واپس لایا جائے، میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائل خودبخود حل ہوجائیں گے۔
جامعہ غوثیہ بھیرہ کے فاضل اور الشریعہ اکادمی کے رفیق پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم ورک نے کہا کہ دینی مدارس کے فضلا کو دوسرے قومی شعبوں میں بطور پالیسی بھجوانے کی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے نصاب تعلیم میں دینی تعلیم کو بنیادی حیثیت دیتے ہوئے عصری تقاضوں کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔ مولانا حکیم عبدالرحمن نے کہا کہ علمائے کرام کو اپنے پاس کوئی ایسا ہنر ضرور رکھنا چاہیے تاکہ وہ کمیٹیوں کے رحم وکرم پر نہ رہیں اور آزادی کے ساتھ مسجد ومدرسہ کی خدمت کرسکیں۔
۱۸؍ ستمبر کو ’’ائمہ وخطباء کی ذمہ داریاں اور ان کی مشکلات ومسائل‘‘ کے عنوان سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا جو صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوکر چار بجے تک جاری رہا۔ اس کی ایک نشست کی صدارت الحاج عثمان عمرہاشمی نے اور دوسری نشست کی صدارت مولانا زاہد الراشدی نے کی اور مولانا سیدعبدالخبیر آزاد خطیب بادشاہی مسجد لاہور اور مولانا مفتی محمد طیب مہتمم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد بالترتیب پہلی اور دوسری نشست کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ خطاب کرنے والوں میں مولانا عبدالرؤف فاروقی، مولانا عبدالحق خان بشیر، مولانا مفتی فخرالدین عثمانی، مولانا عبدالواحد رسول نگری، مولانا حافظ گلزار احمد آزاد، مولانا حافظ محمد رشید اور ڈاکٹر حافظ سمیع اللہ فراز شامل تھے۔
مولانامفتی محمد طیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ مساجد اور ائمہ مساجد کے مسائل کے حل کے لیے باہمی رابطہ واجتماع کا کوئی فورم موجود نہیں ہے، حالانکہ مسائل بھی بہت ہیں اور مشکلات بھی کافی ہیں، مگر باہمی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی مشکلات سے ہی آگاہ نہیں ہوپاتے۔ ان مسائل میں مساجد کے مسائل بھی ہیں اور ائمہ وخطباء کے مسائل بھی ہیں، جبکہ ہر جگہ کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور مسائل میں ہماری ذمہ داریوں کا سوال بھی شامل ہے اور ہماری مشکلات بھی ان مسائل کا حصہ ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کی طرف پوری توجہ دیں تو مشکلات پر کافی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے، مثلاً ہم امامت وخطابت کو ڈیوٹی سمجھتے ہوئے اسی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ مسجد کے فورم سے فائدہ اٹھاکر درس وتدریس، نمازیوں کی ذہن سازی اور نوجوانوں کو تعلیم وتعلم کے ذریعہ قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے دینی فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کے ماحول میں ہمارا اعتماد بھی قائم ہوگا، مگر یہ سارا کام مشنری جذبہ کے ساتھ اور رضاکارانہ انداز میں ہونا چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔
مولانا عبدالرؤف فاروقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سطح کے ائمہ مساجد کے مسائل الگ ہیں۔ دیہات کی مساجد کے مسائل اور ہیں، شہروں کی مساجد کے مسائل مختلف ہیں۔ کمیٹیوں کے تحت چلنے والی مساجد کے ائمہ وخطباء دیگر نوعیت کی مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ خود مسجد بناکر چلانے والے علمائے کرام اور ائمہ کی مشکلات اس سے الگ نوعیت کی ہیں۔ اسی طرح محکمہ اوقاف کی مساجد کے اماموں کے مسائل اور قسم کے ہیں اور فوج یا دیگر سرکاری اداروں کی مساجد کے ائمہ وخطبا کو اس سے الگ نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سب کے تفصیلی جائزہ کی ضرورت ہے۔ الشریعہ اکادمی اس مسئلہ پر مباحثہ کا آغاز کرنے پر مبارک باد کی مستحق ہے لیکن یہ صرف ایک سیمینار کی بات نہیں ہے، اس کے لیے مستقل ورک کی ضرورت ہے تاکہ مسائل کا احساس اجاگر کرکے ان کے حل کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ مولانا فاروقی نے کہا ہمارے بہت سے ائمہ وخطباء اب سے کچھ عرصہ قبل سیاسی ودینی تحریکات میں پیش پیش ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مقامی ماحول اور انتظامیہ کے حوالے سے ان کا رعب ودبدبہ ہوتا تھا، مگر اب غالب اکثریت نے سیاسی عمل، دینی تحریکات اور معاشرتی میل جول سے کنارہ کشی اختیار کررکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہوتے جارہے ہیں۔
مولانا عبدالحق خان بشیر نے اپنے خطاب میں اس ضرورت پر زور دیا کہ خطیب کو جمعہ کے خطبہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور مستند معلومات کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے، اس لیے کہ تیاری اور مستند معلومات کے بغیر کی جانے والی گفتگو ادھوری رہ جاتی ہے، جس کے اثرات منفی ہوتے ہیں اور آج کے دور میں عام لوگوں کے لیے صرف ان خطبائے کرام کے خطبات کشش کا باعث بنتے ہیں، جو باقاعدہ تیاری کرتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر گزارہ کرنے کی بجائے علمی اور معلوماتی مواد اپنے بیان میں پیش کرتے ہیں۔ خطیب کو معاشرتی ضرورتوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، مثال کے طور پر ملک میں یوم کشمیر منایا جارہا ہے تو خطیب کو اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے اور غیرمتعلقہ موضوعات پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے سامعین کو دینی معلومات مہیا کرنے اور احکام ومسائل سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ دینی شخصیات اور اپنے بزرگوں سے بھی متعارف کرائے، جس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بزرگان دین اور بالخصوص اکابرعلمائے دیوبند کا کوئی نہ کوئی واقعہ یا ارشاد موقع محل کی مناسبت سے اپنے خطبات میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مطبوعہ خطبات کے مجموعوں نے ہمارے خطباء کے اندر مطالعہ کا ذوق ختم کردیا ہے، جس کا بہت نقصان ہورہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
مولانا عبدالخبیر آزاد نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں باہمی رابطہ اور مشاورت کو فروغ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مشکلات میں ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے ہم مسلک لوگوں اور نمازیوں کی مشکلات میں بھی حصہ دار بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف جب بات کرتے تھے، ان کی بات کا اثر ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ صاحبِ کردار ہوتے تھے اور ان کی نیکی اور تقویٰ پر لوگوں کا اعتماد ہوتا تھا، آج یہ ماحول کم ہوتا جارہا ہے، ہمیں اپنے معمولات، طرزعمل اور کردار کو بہتر بنانا ہوگا، تبھی ہماری باتوں میں اثر ہوگا اور خاص طو رپر مسلکی معاملات میں حمیت سے کام لینا چاہیے اور مناسب طریقہ سے مسلک اور اہل مسلک کا دفاع کرنا چاہیے۔
مولانا مفتی فخرالدین عثمانی نے کہا کہ ہمارے خطباء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حلال وحرام کے مسائل سے بھی آگاہ کریں اور موقع محل کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری مسائل کو عوام کے سامنے بیان کریں، انہوں نے کہا کہ دینی احکام پر عمل اور نیکی اور تقویٰ کے معاملہ میں ہمیں لوگوں کے سامنے عملی نمونہ بننا چاہیے۔
مولانا عبدالواحد رسول نگری نے کہا کہ ہمارے خطباء کو وقت اور لوگوں کے مزاج کی تبدیلی کا احساس کرنا چاہیے، ایک وقت تھا جب لمبی لمبی تقریریں پسند کی جاتی تھیں اور مشکل جملوں اور محاوروں میں گفتگو کو کمال سمجھا جاتا تھا، اب یہ صورت حال نہیں ہے، آپ سادہ الفاظ میں اور مختصر وقت میں اپنی بات کو سمجھا سکیں تو یہی خطابت کا کمال ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی محسوس کی جانی چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت اور دل چسپی کے مسائل اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو وہ ٹی وی چینلز سے اور دیگر ذرائع سے رجوع کریں گے اور اگر وہی مسائل ہم اچھے انداز میں ان کو سمجھا دیں تو انہیں ادھر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، مگر ہمارے ہاں ان ضروریات کا خیال عام طور پر نہیں رکھا جاتا۔
مولانا حافظ گلزاراحمد آزاد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں خلوص اور مشن کو اپنی محنت کی بنیاد بنانا چاہیے اور قناعت، صبر اور بے نیازی سے کام لینا چاہیے، اس کے ہمیشہ اچھے اثرات سامنے آتے ہیں اور صبر وحوصلہ کا پھل ہمیشہ میٹھا نکلتا ہے۔
ایک نسخہ، بادکے چوراسی امراض کے لیے
حکیم محمد عمران مغل
حضرت کاش البرنی شہید علم رحمۃ اللہ علیہ نے پیر الٰہی بخش کالونی کراچی میں ماہنامہ ’’روحانی دنیا‘‘ کا پودا لگایا تھا جو آج تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس درخت کے پھل پھول سے مسلم وغیر مسلم، ہر طبیعت کے خواتین وحضرات اپنے اپنے مزاج کے مطابق لطف اندوز ہو رہے ہیں۔کہنے کو تو روحانی دنیا ہے، مگر روحانیت کے ساتھ کبھی طبی علاج پر بھی قیمتی مواد بہم پہنچاتے تھے۔ پھر امام بونی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مجرب عملیات وتعویذات کا ایک نایاب ذخیرہ اس میں ہوتا ہے۔ امام غزالیؒ کے علم الحروف کے ایسے ایسے عملیات پیش کیے کہ لندن میں بیٹھے پی ایچ ڈی حضرات بھی بڑے شوق سے یہ عملیات کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ امام غزالیؒ کا یہ علم کرامات سے تعلق رکھتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں لازماً نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ الحمد للہ جب پرچہ کی قیمت آٹھ آنے ہوا کرتی تھی، تب سے اب تک میں اس کا قاری ہوں۔ علم الحروف کے وہ اعمال جن کا تعلق شفاے امراض سے ہے، وہ حکما ومعالجین کرام کے لیے در بے بہا ہیں۔ الغرض علم الحروف ایک مکمل سائنس ہے۔ ادویہ اس کے سامنے ہیچ ہیں۔
کاش البرنی کا خاندان روحانیت کے سمندر میں کافی گہرائی تک غوطہ زن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی نشست میں ان کا علم طب پر ایک نایاب عمل پیش کرتا ہوں۔ اس علم کے بارے میں اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ میری معلومات میں نہ آتا تو ساری زندگی ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا۔ یہ وہ نسخہ ہے کہ عام لوگوں کو ا س کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں عامل کامل اور معالج سادہ لوح لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں۔ جو بھی آیا، اسے کہہ دیا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور بیمار بے چارہ گھر کی ساری جمع پونجی ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے، مگر اس کے جادو کا علاج کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ دراصل ریح والی بادی کا مکمل علاج نہ ہونے سے مریض یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، مگر آپ ایک ہفتہ یہ نسخہ ایسے سحر زدہ مریض پر استعمال کریں تو وہ اقرار کرے گا کہ میرا جادو ختم ہو گیا ہے۔ باد سے ایسے ایسے امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فالج بھی باد سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ نسخہ غیر مذہب کے کسی معالج کی پرانی کتاب سے ترجمہ کر کے پیش کیا گیا ہے جو کئی سو سال پرانا ہے۔ میں نے ایک ہفتہ استعمال کیا تو اپنے آپ کو یوں ہلکا پھلکا محسوس کیا جیسے میں جسم کے بغیر چل پھر رہا ہوں۔ الغرض اس کے استعمال سے جسم کے چوراسی امراض اور دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
ہو الشافی: سونٹھ، سہاگہ، کالا نمک، ہینگ، یہ سب اجزا ہم وزن لے کر کوٹ لیں۔ سہانجنہ کے پانی سے سیاہ مرچ کے برابر گولی تیار کر کے کھانے کے بعد سادہ پانی سے کھا لیں۔ دیکھیں جادو کیسے ختم ہوتا ہے۔ اصل نسخہ کی عبارت یوں ہے:
سونٹھ سہاگہ سونچل گاندھی
وچ سہانجنہ گولی باندھی
سونچل، کالے نمک کو اور گاندھی، ہینگ کو کہتے ہیں۔ کاش البرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت پر بہت کچھ لکھنا باقی ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، ان شاء اللہ۔
نومبر ۲۰۱۱ء
اکابر علماء دیوبند کی علمی دیانت اور فقہی توسع
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
اکابر علماء دیوبند کی خصوصیات اور امتیازات میں جہاں دین کے تمام شعبوں میں ان کی خدمات کی جامعیت ہے کہ انھوں نے وقت کی ضروریات اور امت کے معروضی مسائل کو سامنے رکھ کر دین کے ہر شعبہ میں محنت کی ہے، وہاں علمی دیانت اور فقہی توسع بھی ان کے امتیازات کا اہم حصہ ہے۔ انھوں نے جس موقف کو علمی طور پر درست سمجھا ہے، کسی گروہی عصبیت میں پڑے بغیر اس کی حمایت کی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات کے حوالے سے جہاں بھی فقہی احکام میں توسع اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، انھوں نے اس سے گریز نہیں کیا۔
علماء دیوبند کو بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت او رحنفیت کی علمی اور شعوری ترجمانی کا شرف حاصل ہے جس کا اعتراف عالمی سطح پر کیا جاتا ہے اور ان کے علمی تعارف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکابر علماء دیوبند کو ایک طرف فقہ کی اہمیت وضرورت سے انکار کی صورت حال کا سامنا تھا اور دوسری طرف ان کا واسطہ اس فقہی جمود سے تھا جس میں جزئیات وفروعات کو بھی کفر واسلام کا مدار سمجھ لیا جاتا تھا۔ علماء دیوبند نے ان دونوں کے درمیان اعتدال وتوازن کا راستہ اختیار کیا اور اہل السنۃ اور احناف کے تاریخی علمی تسلسل کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھا۔
اس بات پر چند واقعاتی شہادتیں قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے اکابر علماء دیوبند کے اعتدال، توازن، توسع اور علمی دیانت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
امام الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز اور مولانا احمد رضا خانؒ اپنے دور کی دو بڑی شخصیات ہیں جن کی طرف دیوبندیت اور بریلویت کی علمی روایت منسوب ہے اور عقائد واحکام دونوں میں ان دو شخصیات کی تعبیرات وتشریحات پر ان دو اہم مسلکی گروہوں کے علمی تشخص کا مدار ہے۔ ان کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک سید لڑکی نے جو عاقلہ بالغہ تھی، ایک ایسے شخص سے نکاح کر لیا جس نے خود کو سید ظاہر کیا اور حلف اٹھا کر اس کا یقین دلایا، مگر نکاح کے بعد ظاہر ہو گیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ اس پر لڑکی کے اولیا کو اعتراض ہوا کہ یہ بات ان کے لیے معاشرے میں باعث عار ہے، اس لیے وہ اس نکاح کو قبول نہیں کرتے۔سوال یہ ہوا کہ لڑکے کی طرف سے دھوکہ دینے کے بعد اولیا کے اعتراض کی صورت میں اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر نکاح فسخ کیا جائے تو اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟
اس سوال کے جواب میں مفتی محمد عبد الرحمن برسانی صاحب نے لکھا کہ:
’’صورت مذکورہ میں ہندہ کو اور اولیا کو اختیار فسخ کا ہے۔ اس زمانہ میں اگرچہ قاضی نہیں ہے، جب بھی شہر کے مفتی سے حکم لے کر فسخ کر سکتا ہے کہ قائم مقام قاضی کا مفتی ہے۔‘‘
جبکہ مولانا احمد رضا خانؒ نے اس کا جواب یہ دیا کہ:
’’یہاں جبکہ وہ کفو نہیں اور ولی کو دھوکہ دیا گیا، دونوں امر سے کچھ متحقق نہیں ہوا۔ نکاح باطل محض رہا۔بعد ظہور حال زید کی قسم اور تحریر سب مہمل ہے۔‘‘
مگر یہ استفتاء اور اس کے جوابات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں پیش کیے گئے تو انھوں نے یہ جواب تحریر فرمایا کہ:
’’صورت مندرجہ میں اولیا کو حق فسخ نکاح کا ہے اور وہ کسی حاکم یا قاضی مسلمان سے رجوع کریں کہ وہ فسخ کرے۔ مفتی کو حنفیہ کے نزدیک بغیر تحکیم طرفین اختیار فسخ نہیں ہے۔‘‘
اس پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ اور حضرت مولانا محمد منفعت علیؒ کے بھی دستخط ہیں۔ یہ سب فتاویٰ جب دار العلوم دیوبند کے اس وقت کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ کے سامنے رکھے گئے تو انھوں نے اس پر تحریر فرمایا کہ: ’’جواب مجیب اول صحیح ہے۔ اولیا کو اختیار فسخ نکاح ہے۔‘‘
یہ علمی دیانت کی بات ہے کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ کو خود اپنے مشائخ اور اساتذہ کی راے پر اطمینان نہیں ہوا تو انھوں نے دوسرے فریق کے موقف کی حمایت کر دی اورمزید دیانت کی بات یہ ہے کہ جب فتاویٰ رشیدیہ مرتب کیا گیا تو اس میں یہ سارے جوابات من وعن شامل کر دیے گئے اور اب بھی یہ سوال وجواب ’’فتاویٰ رشیدیہ‘‘ کا حصہ ہیں۔
میں نے جب یہ فتویٰ پڑھا تو میرے ذہن میں حضرت امام بخاریؒ کے ایک واقعہ کی یاد تازہ ہو گئی جو کسی زمانے میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب ’’قواعد علوم الحدیث‘‘ کے حاشیہ میں حضرت الاستاذ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم سے نظر سے گزرا تھا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے معتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے ’’القرآن کلام اللہ غیر مخلوق‘‘ کے عقیدہ پر سختیاں برداشت کی تھیں اور قید اور کوڑوں کی سزائیں جھیلی تھیں، مگر ان کے بعد بعض حنابلہ نے اس عقیدہ کی تعبیر وتشریح میں غلو اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہماری زبانوں پر تلاوت میں آتے ہیں، یہ بھی مخلوق نہیں ہیں تو حضرت امام بخاریؒ نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ ’’لفظی بالقرآن مخلوق‘‘۔ اس پر حضرت امام بخاریؒ کے استاذ محترم امام محمد بن یحییٰ نیساپوریؒ نے امام بخاریؒ کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دے دیا اور فرمایا کہ:
’’من زعم لفظی بالقرآن مخلوق فہو مبتدع ولا یجالس ولا یکلم ومن ذہب بعد ہذا الی محمد بن اسماعیل البخاری فاتہموہ فانہ لایحضر مجلسہ الا من کان علی مذہبہ‘‘
’’جو شخص یہ کہتا ہے کہ ’’لفظی بالقرآن مخلوق‘‘ وہ بدعتی ہے۔ اس کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے اور اس سے کلام نہ کیا جائے اور جو شخص اس کے بعد محمد بن اسماعیل بخاریؒ کی مجلس میں جائے، اسے متہم سمجھا جائے، کیونکہ اس کی مجلس میں وہی جاتا ہے جواس کے مذہب پر ہوتا ہے۔‘‘
حضرت امام بخاریؒ نے بھی اپنے استاذ حضرت امام محمد بن یحییٰ ذہلیؒ کے شہر میں اپنا حلقہ درس قائم کیا تھا، مگر جب امام ذہلیؒ نے یہ فتویٰ صادر کر دیا: ’’لا یساکننی محمد بن اسماعیل فی البلد‘‘ کہ محمد بن اسماعیل اس شہر میں میرے ساتھ نہ رہے تو امام بخاریؒ کو نیشاپور چھوڑنا پڑا اور وہ اپنے وطن بخارا چلے گئے جہاں کے گورنر خالد کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا اور وہ وہاں سے بھی نکل گئے او رمسافرت کی حالت میں ’’خرتنگ‘‘ کے مقام پر یہ دعا کرنے کے بعد وفات پا گئے کہ ’’اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک‘‘، یا اللہ، یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ پڑ گئی ہے، اس لیے اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔‘‘ مجھے علماء کرام کے ایک وفد کے ساتھ خرتنگ جانے اور امام بخاریؒ کی قبر پر فاتحہ خوانی کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔
اس واقعہ کے حوالے سے عام طور پر میں دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اہل سنت کے ہاں عقائد میں بھی تعبیرات وتشریحات کے تنوع اور توسع کی یہ کیفیت ہے کہ امام ذہلی اور ان کے متبعین الفاظ قرآن کے مخلوق ہونے کو ’’القرآن کلام اللہ غیر مخلوق‘‘ کے عقیدے کے خلاف اور بدعت قرار دے ہیں، جبکہ امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ کو ’’لفظی بالقرآن مخلوق‘‘ کہنے پر نیشاپور سے جلاوطن ہونا پڑا ہے، مگر اس کے باوجود دونوں طبقوں اور ان کے نمائندہ بزرگوں کو اہل سنت کے مسلمہ اماموں کا درجہ حاصل ہے اور امت دونوں کے ساتھ نسبت پر فخر کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الاستاذ ابو غدہؒ نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاذ محترم امام ذہلیؒ کے اس سخت رویے اور ان کی طرف سے گمراہی کے فتوے اور جلا وطنی کے حکم کے باوجود ان سے روایت ترک نہیں کی اور بخاری شریف میں ان سے تیس کے لگ بھگ روایات درج کی ہیں۔ یہ علمی دیانت ہے جو ہمارے پرانے اسلاف کی روایات کا حصہ ہے اور اکابر علماء دیوبند نے اس کا تسلسل قائم رکھا ہے۔
اس سلسلے میں دوسرا واقعہ یہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قدس اللہ سرہ العزیز کے معاون اور نائب کے طور پر ذمہ داریاں ۱۹۷۰ء میں سنبھالی تھیں، لیکن اس سے قبل بھی ان کی غیر موجودگی میں جامع مسجد میں جمعہ پڑھانے کا متعدد بار اعزاز حاصل ہو چکا تھا۔ یہاں میں نے اپنے عمومی ماحول سے ایک مختلف بات یہ دیکھی کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر خطب کے سامنے لاؤڈ اسپیکر پر نہیں دی جاتی، بلکہ مسجد کی حدود سے باہر امام کے سامنے حوض پر کھڑے ہو کر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دی جاتی ہے، جبکہ گکھڑ میں حضرت والد محترمؒ اور مدرسہ نصرۃ العلوم میں حضرت صوفی صاحبؒ کا معمول یہ تھا کہ موذن جمعہ کی اذان ثانی لاؤڈ اسپیکر پر امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا تھا۔
مجھے اس پر الجھن ہوئی تو میں نے حضرت مولانا مفتی عبد الواحدؒ سے دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک جمعہ کی اذان ثانی مسجد کی حدود سے باہر دینا بہتر ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ مسجد کے صحن کے آخر میں جو حوض ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم اعتکاف کرنے والوں کو وہاں تک جانے سے منع کرتے ہیں اور ہمارا موذن جمعہ کی اذان ثانی حوض پر امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ میں نے اس کے بعد مزید اس مسئلہ کی کرید کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے کہ اس قسم کے جزوی اور فروعی مسائل میں میرا ذوق او رمعمول یہ ہے کہ جہاں کسی ذمہ دار بزرگ کے فتویٰ پر عمل ہو رہا ہو، میں وہاں اسی پر عمل کرتا ہوں اور اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔
حضرت مولانا مفتی عبد الواحدؒ ہمارے اکابرمیں سے تھے، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفرازخان صفدرؒ کے استاذ تھے اور میں نے کئی بار حضرت والد محترمؒ کو بعض مسائل میں ان سے رجوع کرتے دیکھ رکھا تھا، اس لیے میں بھی کم وبیش بیالیس سال سے ان کے فتویٰ پر عمل کرتا آ رہا ہوں اور اب بھی اس پر کسی نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کا پس منظر کافی عرصہ کے بعد اس وقت میر ے علم میں آیا جب حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود مدظلہ العالی کی کتاب ’’مطالعہ بریلویت‘‘ سامنے آئی جس میں انھوں نے اس مسئلے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ فتویٰ دراصل مولانا احمد رضا خان کا تھاکہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کی حدود سے باہر ہونی چاہیے۔ اس مسئلہ پر مولانا احمد رضا خان بریلویؒ کا اپنے بہت سے معاصر علماء کرام سے تحریری مباحثہ بھی ہوتا رہا اور ان کے معاصر علماء کرام نے، جن میں دیوبندی اور بریلوی دونوں شامل ہیں، ان کے اس فتویٰ سے اتفاق نہیں کیا تھا، مگر ہمارے ہاں مرکزی جامع گوجرانوالہ میں جمعہ کی اذان ثانی مسجد کی حدود سے باہر حوض پر دیے جانے کا معمول چلا آ رہا ہے۔
تیسری بات اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مزارعت یعنی بٹائی کا مسئلہ ائمہ احناف میں مختلف فیہ رہا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ اسے جائز نہیں سمجھتے اور صاحبین یعنی حضرت امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ مفتیٰ بہ قول ہر دو ر میں صاحبین کے قول کو قرار دیا جاتا رہا ہے او ر آج بھی احناف کے ہاں اسی فتویٰ پر عمل جاری ہے، لیکن پاکستان میں جب بڑی زمین داریوں اور جاگیرداریوں کو عوامی مفادات اور ضروریات کے لیے کنٹرول کرنے کا مسئلہ چلا تو ۷۰ء میں علماء دیوبند کی سب سے بڑی جماعت جمعیۃ علماء اسلام پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا قول اگرچہ مفتیٰ بہ نہیں ہے، لیکن امت کی اجتماعی ضرورت اور مفاد کے لیے اس مرجوح فتویٰ پر عمل کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس موقف کا تذکرہ جمعیۃ علماء اسلام کے ۱۹۷۰ء کے انتخابی منشور میں موجود ہے اور حضرت مولانا مفتی محمودؒ نے مختلف مواقع پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب کے سوانح نگار مولانا ڈاکٹر عبد الحکیم اکبری کی تصنیف ’’مولانا مفتی محمود کی علمی، دینی وسیاسی خدمات‘‘ (صفحہ ۵۰۰) سے اس سلسلے میں ایک اقتباس یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔
حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکیؒ نے کراچی میں علما کی مجلس کا ذکر کرتے ہوئے اس میں بیان کردہ حضرت مولانا مفتی محمودؒ کے موقف کا یوں تذکرہ فرمایا ہے:
’’مزارعت کا مسئلہ زیر بحث آیا تو حضرت مفتی صاحبؒ نے بڑی فاضلانہ تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس زمانہ میں مزارعت کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاریوں کو زمیندار غلام سمجھتے ہیں اور چونکہ مسئلہ اختلافی ہے، ائمہ کبار میں سے حضرت امام ابوحنیفہؒ اس کے خلاف ہیں، اس لیے ان کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے اگر مزارعت کی ممانعت کر دی جائے اور مالکان زمین سے کہا جائے کہ وہ ملازم رکھ کر کاشت کرائیں یا خود کاشت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔‘‘
یہ سب باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند کا طرز عمل جزئیات وفروعات پر اڑے رہنے اورچند مخصوص فتاویٰ پر جمود اختیار کرنے کا نہیں رہا، بلکہ حالات وزمانہ کے تقاضوں اور امت کی معروضی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری علمی دیانت،اعتدال اور فقہی توسع کے ساتھ امت کے لیے سہولتیں پیدا کرنے اور اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے حالات کی ضروریات کو ایڈجسٹ کرنے کا رہا ہے اور آج بھی اکابر علماء دیوبند کی یہی روایت ہم سب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔
مشترکہ دینی تحریکات اور حضرت امام اہل سنتؒ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
تحریک ختم نبوت، تحریک تحفظ ناموس رسالت اور تحریک نفاذ شریعت کے لیے مشترکہ دینی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت پر ہمارے بعض دوستوں کو اعتراض ہے۔ یہ اعتراض ان کا حق ہے اور اس کے لیے کسی بھی سطح پر کام کرنا بھی ان کا حق ہے۔ اسی طرح اعتراض کو قبول نہ کرنا ہمارا بھی حق ہے جس کے بارے میں ہم نے مختلف مواقع پر اپنے موقف کا تفصیل کے ساتھ اظہار کیا ہے اور ضرورت کے مطابق آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
اس سلسلے میں ہمارے والد گرامی امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے جو محل نظر ہے اور اس حوالے سے حضرت امام اہل سنتؒ کی زندگی کے چند اہم مراحل کی طرف توجہ دلانا مناسب معلوم ہوتا ہے:
- قیام پاکستان سے قبل حضرت امام اہل سنتؒ مجلس احرار اسلام کے باقاعدہ کارکن رہے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس دور میں آل انڈیا مجلس احرار اسلام کے سیکرٹری جنرل معروف شیعہ عالم دین مولانا مظہر علی اظہر تھے۔
- قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں حضرت امام اہل سنتؒ شریک رہے ہیں اور متعدد جلوسوں کی قیادت کی ہے بلکہ ازخود گرفتاری دے کر کم وبیش نو ماہ جیل میں رہے ہیں۔ اس تحریک کی قیادت میں اہل تشیع شریک تھے۔
- ۱۹۵۱ء میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں تمام مکاتب فکر کے اکابر ۳۱؍ علماء کرام کے طے کردہ ۲۲ متفقہ دستوری نکات کی حضرت امام اہل سنت نے ہمیشہ حمایت کی ہے اور وہ ملک میں ان کے نفاذ کا مسلسل مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ان ۲۲ نکات کی ترتیب وتدوین میں بھی اکابر شیعہ علما شریک تھے۔
- ۱۹۷۷ء میں نظام مصطفی کے نفاذ کی تحریک میں حضرت امام اہل سنت نے بھرپور کردار ادا کردار ادا کیا ہے، عوامی جلوسوں کی قیادت کرتے رہے ہیں اور ایک جلوس کی قیادت کر کے ازخود گرفتاری پیش کی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے فرزند مولانا عبد الحق خان بشیرکے ہمراہ ایک ماہ تک ڈسٹرکٹ جیل گوجرانوالہ میں قیدرہے ہیں۔ اس تحریک کی قیادت میں بھی اہل تشیع شریک تھے۔
- ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت میں امام اہل سنتؒ نے حضرت السید مولانا محمد یوسف بنوریؒ کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور اس تحریک کی مرکزی مجلس عمل میں اہل تشیع شریک تھے۔
- مشترکہ دینی وسیاسی تحریکات میں جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کی شمولیت کے مسئلہ پر اختلاف کے باعث حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا عبد اللطیف جہلمیؒ اور ان کے رفقا نے جمعیۃ سے الگ ہو کر جب تحریک خدام اہل سنت قائم کی تو حضرت امام اہل سنت نے اپنے ان بزرگ دوستوں کے تمام تر احترام اور ان کی دینی خدمات کے بھرپور اعتراف کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے بعد بھی جمعیۃ علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر مشترکہ دینی تحریکات میں انھوں نے ہمیشہ حصہ لیا ہے۔
- حضرت امام اہل سنتؒ کی علالت کے دور میں جب متحدہ مجلس عمل تشکیل پائی تو انھوں نے عام انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کی کھل کر حمایت کی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں کام کرنے کی ہدایت کی، جبکہ متحدہ مجلس عمل کی قیادت میں اہل تشیع موجود تھے اور اپنے حلقہ سے حضرت امام اہل سنتؒ نے قومی اسمبلی کے لیے متحدہ مجلس عمل کے جس امیدوار جناب قدرت اللہ بٹ کی حمایت کی، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے بلکہ وہ اس وقت جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ کے امیر تھے۔
متحدہ مجلس عمل کے قیام کی تائید اور حمایت اس حوالے سے بطور خاص قابل توجہ ہے کہ بعض حضرات یہ استدلال پیش کر رہے ہیں کہ حضرت امام اہل سنت نے ’’ارشاد الشیعہ‘‘ تصنیف کر کے دینی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت کے حوالے سے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کر لیا تھا، حالانکہ ارشاد الشیعہ کا سن تصنیف ۱۹۸۷ء ہے جبکہ متحدہ مجلس عمل کا قیام ان کی عمر کے آخری دور میں جنرل پرویزمشرف کے زمانے میں ہوا تھا۔
مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں اپنے ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ دینی تحریکات میں اہل تشیع کی شمولیت پر اپنے اعتراض کا حق ضرور استعمال کریں اور اس کے لیے جائز حدود میں مہم بھی چلائیں،لیکن مشترکہ دینی تحریکات کی حد تک اس سلسلے میں امام اہل سنتؒ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدرؒ کا نام استعمال نہ کریں، اس لیے کہ امام اہل سنتؒ خود زندگی بھر ایسی تحریکات کا حصہ رہے ہیں۔
قومی سلامتی۔ نئے حقائق، نئے تقاضے
سلیم صافی
عید الفطر کے موقع پر طالبان کے سربراہ ملا محمد عمر مجاہد اور حزب اسلامی کے امیر گلبدین حکمت یار کے جاری کردہ تفصیلی پیغامات نظروں کے سامنے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر ان کے یہ پیغامات دراصل پالیسی بیانات ہوتے ہیں جن میں افغان قضیے کے تمام پہلووں کا احاطہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کی بار دونوں کے پیغامات کا لب ولہجہ ماضی کے لب ولہجے سے بہت مختلف اور بنیادی سوچ بڑی حد تک یکساں ہے۔ دونوں کے پیغامات میں کسی بھی شکل میں افغانستان کے اندر غیر ملکی افواج یا پھر ان کے اڈوں کی موجودگی کو ناقابل برداشت قرار دیا گیا ہے۔ جہاں غیر ملکیوں کے بارے میں لہجہ بے لچک اور سخت ہے، وہاں کرزئی حکومت پر ماضی کے برعکس کوئی تبرا نہیں بھیجا گیا ہے۔
ملا محمد عمر نے اپنے پیغام میں پہلی بار نیا پیغام دیا ہے کہ غیر ملکیوں کے نکلنے کے بعد سوویت یونین کے انخلا کے بعد کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان تمام افغانوں کا ملک ہے اور نئے نظام میں تمام طبقات کو سمونے کی کوشش کی جائے گی۔ افغانستان کے قدرتی وسائل او رمعدنی وسائل کے تذکرے کے بعد انھوں نے ان سے استفادہ کرنے اور غربت وبدحالی کو نشانہ بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے جبکہ دنیا اور پڑوسی ممالک کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کی بات کی گئی ہے۔ انھوں نے اپنے پیروکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ نظم وضبط کا مظاہرہ اور غیر متحارب انسانوں کو دکھ پہنچانے سے گریز کریں۔ گلبدین حکمت یار تو دو قدم آگے بڑھ کر مجاہدین پر زور دیتے ہیں کہ وہ سرکاری حکام، اساتذہ، ججوں، علما، انجینئروں، ڈاکٹروں، صحافیوں اور غیر متحارب لوگوں کو مارنے سے گریز کریں اور یہ تک کہہ گئے کہ مساجد، مدارس، اسکولوں، ہسپتالوں، دفتروں اور پبلک مقامات پر دھماکے کرنے والے دشمن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔
مذکورہ دونوں افغان رہنماؤں نے پڑوسی ممالک اور بالخصوص پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن ان پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کی خاطر افغانوں کے خلاف سازش کا حصہ نہ بنیں۔ ان پیغامات میں چھپا پیغام، جہاں تک میں سمجھا ہوں، یہ ہے کہ طالبان اور حکمت یار کی طرف سے کابل اور اسلام آباد کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ امریکی اثر سے آزاد ہو کر غیر ملکی افواج کے انخلا میں تعاون کریں تو وہ ماضی کی طرح صرف ایک طبقے کی حکومت قائم کرنے پر اصرار نہیں کریں گے۔ حکمت یار تو خیر پہلے سے ہی انتخابات اور وسیع البنیاد حکومت کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اب طالبان کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رویے کو نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی برادری اور خطے کے ممالک کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔
ملا محمد عمر نے اس پیغام میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا بھی اعتراف کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو امریکیوں نے قضیے کے حل کے لیے باقاعدہ مذاکرات کی شکل میں پیش کیا۔ انھوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ صرف قیدیوں کے تبادلے کے جزوی مسئلے پر ہونے والے مذاکرات کسی صورت قضیے کے حل کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ میری ذاتی معلومات کے مطابق طالبان رہنما طیب آغا گزشتہ ماہ تک امریکی رابطے میں تھے، لیکن اب طالبان نے یہ سلسلہ مکمل طو رپر ختم کر دیا ہے اور طیب آغا چند روز قبل ایک خلیجی ملک سے پراسرار طور پر غائب ہو گئے، حالانکہ امریکی ان کا انتظار کرتے رہ گئے۔
گویا طالبان اب امریکہ کے ساتھ براہ راست معاملہ کرنے کی بجائے افغان اور پاکستان حکومتوں کے ساتھ مکالمے کا عندیہ دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو بااختیار ثابت کرنا اور فضا سازگار بنانا ان حکومتوں کا کام ہے۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ کابل اور اسلام آباد مزید قریب آئیں، وہ امریکہ اور طالبان سے متعلق ایک ہی راستہ اپنا لیں اور خطے سے غیر ملکی افواج کے انخلا اور طالبان یا پھر حزب اسلامی کے ساتھ مفاہمت کے لیے ایک مشترکہ اور قابل عمل فارمولا سامنے لائیں۔ یقیناًیہ یکسر ایک نئی صورت حال ہے اور پاکستانی پالیسی سازوں کو اس کے تناظر میں اپنی پالیسی ازسرنو مرتب کرنی چاہیے۔
(بشکریہ روزنامہ جنگ، ۶ ستمبر ۲۰۱۱ء)
ہم ۔ دنیا بھر کے تنازعات کے امپورٹر!
مولانا مفتی محمد زاہد
عالمِ عرب میں اس وقت جو عوامی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ جہاں پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں، وہیں پاکستان سمیت عالم اسلام کی ان سے دلچسپی ایک فطری امر ہے۔ تاہم ان تحریکوں نے خلیجی ریاستوں میں پہنچ کر کسی قدر فرقہ وارانہ رنگ بھی اختیار کرلیاہے یا یہ رنگ انہیں دے دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اس مسئلے کے حوالے سے کسی قدر کشیدگی کا عنصر بھی آرہا ہے۔ پہلے تو بحرین اور سعودی عرب کے بعض واقعات یا مسائل کی وجہ سے ایک فریق نے سعودی عرب کے فرماں روا خاندان کے خلاف نفرت آمیز بینرز لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے جواب میں دوسرے فریق نے نہ صرف یہ کہ سعودی حکومت اور نظام کی حمایت میں بلکہ ایک مخصوص فرقے اور پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک کے خلاف ایک مہم شروع کردی۔ مئی کے مہینے میں پاکستان میں جو سنگین واقعات رونما ہوئے، ان کے نتیجے وقتی طور پر تو یہ مسئلہ دب گیا ہے، لیکن اخبارات کے اندرونی صفحات کی بعض چھوٹی چھوٹی سرخیوں سے، جنہیں بعض اوقات نظر انداز کرنا آسان یا مناسب نہیں ہوتا، یہ خدشہ پیدا ہورہاہے کہ کہیں یہ سلسلہ دوبارہ نہ چل نکلے۔ مجھے خود اس مسئلے کے بارے میں کسی موقف کی حمایت یا مخالفت میں تو کچھ عرض نہیں کرنا، البتہ مسئلے کی نوعیت اپنے ملک کے عمومی رویے، جس کا تعلق فریقین کے ساتھ ہے، کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے ۔
اس مسئلے کے اہم فریق ایران اور سعودی عرب سمیت خلیج کی بعض دولت مند سنی ریاستیں ہیں۔ دونوں فریقوں کے حوالے سے مسئلے کے کچھ تو بین الاقوامی پہلوہیں اور کچھ کا تعلق ان ملکوں کے اندرونی حالات سے ہے۔ ایران جس خطے میں واقع ہے، وہاں دنیا کی ایک عظیم سلطنت یعنی کسریٰ کی سلطنت یا ساسانی سلطنت قائم رہی ہے۔ اس سلطنت کا اردگرد کے علاقوں پر اثر ورسوخ بھی رہاہے۔ خصوصاً خلیج کی متعدد ریاستوں کے علاقے تاریخی طور پر اس سلطنت کے زیرِ اثر رہے ہیں۔ ایران کی قومی نفسیات میں یہ بات اب بھی جاگزیں ہے، اس کے اثرات ظاہر ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں بھی ہوسکتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ موجودہ ایران کی آبادی کا بڑا حصہ اہل تشیع سے تعلق رکھتاہے اور شیعیت ہی ایران کا سرکاری مذہب یا فرقہ ہے۔ لیکن ایرانی نفسیات کے مذکورہ پہلو کو فرقہ وارانہ کی بجائے اس کے قومی یا نسلی تناظر میں دیکھنا شاید زیادہ مناسب ہو۔ چنانچہ ایران ایک سیکولر سٹیٹ بھی بن جاتاہے، تب بھی بظاہر یہ بات اس کی سائیکی کا کسی نہ کسی طرح حصہ رہے گی کہ وہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ساسانی سلطنت جیسی عظیم سلطنت قائم کی تھی جو خلیج کے بیشتر حصوں پر اپنا اثر ورسوخ رکھتی تھی۔ یہی پہلو ایران کے حوالے سے عرب ریاستوں میں خطرے کا احساس پیدا کرتاہے۔ خاص طور پر جبکہ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ملالی جائے کہ عرب خلیجی ریاستوں کے مقابلے میں معاشی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود فوجی طاقت اور سائنس وٹیکنالوجی میں ایران ان ریاستوں سے کہیں فائق ہے۔ فوجی اور سائنسی طور پر مضبوط ایران کا ایک قومی احساسِ تفاخر اور عربوں کا اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرنا موجودہ مسائل کی ایک وجہ ہے۔
اگر اس مسئلے کے داخلی پہلو کو دیکھیں تو ایران اگرچہ ایک جمہوریہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انقلاب کے بعدسے وہ ایک مذہبی ریاست ہے ،بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ ایک طرح سے تھیوکریسی کی حامل ریاست بھی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران میں بڑی تعداد میں وہ طبقہ بھی موجود ہے جو موجودہ سیٹ اپ یا نظام سے خوش نہیں ہے اور وہ ایران میں زیادہ شخصی آزادیوں کااور ایک خاص فرقے ہی کے مذہبی طبقات کے ریاستی امور میں گہرے اثر ورسوخ میں کمی کا خواہاں ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اصلاح پسند کہلاتے ہیں اور بظاہر وہاں کی غیر شیعہ آبادی کی ہمدردیاں بھی اصلاح پسندوں ہی کو حاصل ہوں گی۔ اصلاح پسندوں کی طاقت کا اندازہ صدر احمدی نژاد کے دوسرے انتہائی متنازعہ انتخابات سے لگایا جاسکتاہے۔ وہی ایران جو بعض دیگر ملکوں میں جمہوریت اور شخصی حقوق کی بات کرتاہے، خود اس میں حکومت کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس کی تفصیل یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایران میں خود ایک منتخب صدر مذہبی اشرافیہ کے سامنے کتنا بے بس ہے، اس کا اندازہ گذشتہ ہفتوں کے واقعات سے بخوبی لگایا جاسکتاہے اور اس سے پتا چلتاہے کہ وہاں کتنی جمہوریت ہے اور کتنی تھیوکریسی۔ ظاہر ہے اس ساری صورتِ حال پر وہاں کے عوام نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگلے انتخابات میں وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ جو عوام رضا شاہی بادشاہت ختم کرسکتے ہیں، وہ کسی وقت آیت اللہی بادشاہت بھی ختم کرسکتے ہیں۔ حاصل یہ کہ ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اندورنی حقیقی عوامی خطرہ موجودہے، ایسے میں خطے میں فرقہ وارانہ تناؤ کی فضا اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ساز گار ہے۔ اس سے وہ اپنے ملک کے اکثریتی فرقے کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوجاتی ہے کہ ان کے ہم مذہب لوگوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اور موجودہ سیٹ اپ ان خطرات میں اس فرقے کی بھر پور مدد کررہاہے۔ اس طرح سے اصل اندرونی مسئلے سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے میں اسٹیبلشمنٹ کو سہولت ہوجاتی ہے۔
اندرونی حالات کے اعتبار سے تقریباً یہی معاملہ عرب ملکوں کاہے۔طویل عرصے سے ان ملکوں میں شخصی حکومتوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں شخصی آزادیوں کی صورتِ حال ناقابلِ رشک ہے۔ ایک عرصے تک تو دولت کی فراوانی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر کام چلتا رہا، لیکن جدید ترین ذرائعِ ابلاغ و مواصلات اور نئی نسل کے باہر کی دنیا سے رابطے اور تأثر کے نتیجے میں بالخصوص بغیر تیل کے عرب ملکوں کی حالیہ عوامی تحریکات نے تیل والے عرب ملکوں کے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ایک نئی بیداری پیداکی ہے جسے زیادہ عرصے تک شاید نظر انداز نہ کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں عورت کے ڈرائیونگ کرنے پر پابندی ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے جو یقیناسعودی عرب سے باہر کسی ملک میں رہی ہوگی اور وہیں سے ڈرائیونگ سیکھی ہوگی، خود کار ڈرائیو کرکے اس کی ویڈیوکو یوٹیوب پر اپ لوڈ کردیا جس پر اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ قائم ہوا۔ مقدمے میں ذکر کردہ جرائم میں ملک کو بدنام کرنے کی کوشش بھی شامل ہے۔ اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ کچھ خواتین نے ایک اور وقت متعین کرکے یہی کام کیاہے۔ اب ان کے خلاف کیا ہوگا ، یہ معلوم نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سعودی نظام کب تک نئی نسل کو یہ باور کرائے گا کہ عورت کا ڈرائیونگ کرنا خلافِ اسلام ہے؟ سعودی عرب نے جو فہم دین دوسروں ملکوں کو سپلائی کیا ہے، اس کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ کسی کے اجتہاد یا استنباط کو ماننے کی بجائے خود قرآن وحدیث سے حکمِ شرعی جاننا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ نوجوان نسل یہ پوچھے گی کہ عورت گاڑی نہیں چلاسکتی، یہ کون سی آیت یا حدیث میں آتاہے؟ یہ تو محض ایک مثال ہے، وگرنہ شخصی آزادیوں پر قدغنوں اور دینی امور پر ایک خاص طبقے کی اجارہ داری پر بہت کچھ کہا جاسکتاہے۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک میں شخصی آزادیوں کے حوالے سے موجودہ نظام سے اکتاہٹ پیدا ہونا یہ حقیقی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کا ایک آسان راستہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ہے کہ کسی بیرونی خطرے کا ہوا کھڑا رہے۔ اس کے لیے موجودہ شیعہ سنی یا عرب ایران تناؤ کافی کار آمد ہوسکتاہے۔ چنانچہ چند ہفتے پہلے راقم الحروف نے حرمین شریفین کی حاضری کے موقع پر اس کے اثرات محسوس کیے۔ پہلی حاضریوں کے موقع پر عموماً وہاں پر موجود پاکستانیوں کی زبان پر مواطن (سعودی شہری) اور اجنبی کے درمیان روا رکھی جانے والی تمیز ہوتی تھی اور اس حوالے سے وہ کافی شکوہ کناں نظر آتے تھے، لیکن اس دفعہ کم از کم دینی ذہن رکھنے والے پاکستانیوں کی زبان پر شیعہ خطرے کی بات تھی جس کا مطلب یہ ہوا کہ تناؤ کی اس صورتِ حال نے ان کے لیے حقوق کے مسئلے کو پس پشت ڈال دیاہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتِ حال کسی بھی ملک کے حکمران سیٹ اپ کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے۔حا صل یہ کہ موجودہ تناؤ کی کیفیت ایران اور تیل والے عرب ملکوں دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اندرونی مسائل کے حوالے سے سود مندہے۔
یہاں جو بات اصل میں عرض کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ان ملکوں کے اندرونی مسائل کا ساخشانہ ہے یا بعض علاقائی مسائل کا۔ ایک پاکستانی کو کسی بھی وجہ سے ان میں سے ایک فریق سے ہمدردی بھی ہوسکتی ہے، اس حوالے سے وہ اظہار رائے بھی کرسکتاہے، لیکن بہر حال بنیادی طور پر یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ماضی کے تجربات کے پیش نظر جس چیز کا خطرہ ہے اور جس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں یہ جنگ پاکستان کی سرزمین پر منتقل نہ ہوجائے۔ ایرانی ہوں یا عرب، وہاں کے شیعہ ہوں یا سنی، انہیں اپنے معاملات میں کسی پاکستانی شیعہ یا سنی کی مدد یا اس کے جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے ان کے اپنے ’طریقے‘ ہیں جنہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان کی سرزمین پر پہلے ہی اتنے مسائل اور اتنے تنازعات موجود ہیں کہ ہم مزید کسی تنازعہ کو درآمد کرنے کے متحمل نہیں ہوسکتے۔
ایک صاحب سے، جو اس سارے معاملے کو شیعہ سنی تناظر ہی میں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا کہ اگر واقعی یہ سنی شیعہ مسئلہ ہے تو سعودی عرب جیسے ملکوں کو چاہیے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کو، خاص طورپر جو بیسیوں سالوں سے وہاں مقیم ہیں، جلد از جلد اپنے ہاں کی شہریت دے دیں کیونکہ ان کی بڑی اکثریت سنی ہے، اس لیے اس سے وہاں سنیوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ حرمین کا صدیوں سے یہ کردار رہا ہے کہ جو لوگ مشاہیر اہل علم سے ان کے اوطان میں جاکر استفادہ نہیں کرسکتے تھے، حج وعمرہ ایسے علما سے ایسے لوگوں کے استفادے کا پڑا اہم ذریعہ ہوتا تھا۔ اب موجودہ نظام میں نہ صرف یہ کہ حرمین کا صدیوں کا یہ کردار نہیں رہا بلکہ ا س کی شدت سے حوصلہ شکنی کی جارہی ہے۔ مخصوص سوچ کے حامل لوگوں کے علاوہ، خواہ وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس سے سرسری ملاقات، زیارت یا محض مصافحہ کرنے والوں کی کچھ تعداد ہوجائے تو وہاں کے ادارے چوکنا ہوجاتے ہیں۔ پہلے بھی یہ صورتِ حال تھی، لیکن اس دفعہ کی حاضری میں راقم الحروف نے اس حوالے سے مشاہیر اہل علم کوپہلے سے کہیں محتاط پایا کہ حتی الامکان میل ملاقات سے گریز کیا جائے۔ خواہ یہ بات ایران اور سعودی عرب دونوں کو حامیوں کو کڑوی لگے، لیکن حقیقت بہر حال یہی ہے کہ ایران اپنے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہتا ہے، لیکن عملاً وہاں اسلام کی نہیں، ایک مخصوص فرقے کی حکومت ہے۔ اسی طرح سعودی عرب لاکھ اپنے ہاں مکمل شریعت نافذ کرنے کا دعویٰ کرے، وہاں شریعت کی نہیں، اسلام اور شریعت کے حوالے سے محض ایک سوچ کی حکمرانی ہے۔
ایک عرصے سے پاکستانی معاشرہ دنیا بھر کے تنازعات کا بہت بڑا امپور ٹر بنا ہوا ہے۔ ہمارے دو پڑوسی ملکوں میں الگ الگ وقتوں میں انقلاب آئے، ان دونوں کو خالص اسلامی اور مثالی انقلاب قرار دے کر پاکستان میں در آمد کرنے کی کوشش یا بات کی گئی۔ اسّی کی دہائی میں ایران عراق یا ایران عرب جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ ایران عراق سرحد پر اتنی شدت سے نہیں لڑی گئی جتنی پاکستان کے گلی محلوں میں لڑی گئی۔ ان دو ملکوں کی سرحد پر جنگ ختم ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں یہ لڑائی جاری رہی اور اس میں اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا جو محتاجِ بیان نہیں۔ امریکا نے عرب دنیا میں اپنے بعض مہروں کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے جنہیں بہانہ بہا کر اس نے خطے میں اپنی فوجیں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب سمیت بعض عرب ملکوں نے اپنی کئی مجبوریوں کی وجہ سے امریکی فوجوں کو اڈے دیے، یہ اس خطے میں امریکا کے حسی وجود(physical existence) کی سب سے پہلی شکل تھی۔ اس پر ایک سعودی مجاہد اسامہ بن لادن ؒ نے صدائے احتجاج بلند کی اور بجا طور پر کہا کہ اگر محض صدام کے خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکی فوجوں کو اڈے دیے گئے ہیں تو اس مسئلے کے کئی متبادل حل بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی ، بلکہ اس کے شاہی خاندان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کشیدہ ہوگئے۔ اسامہ کا اصل درد جزیرۂ عرب سے امریکی فوجوں کو نکالنا تھا، لیکن یہ وہاں کے شاہی نظام کا کرشمہ تھا کہ امریکیوں کی بجائے خود اسے جزیرۂ عرب سے نکل کر اور جزیرۂ عرب سے غیر مسلم فوجوں کے نکالنے کا مشن لے کر در بدر ہونا پڑا۔ دوسری طرف مصرمیں جمال عبد الناصر اور اس کے ’خلفا‘ کے ہاتھوں الاخوان المسلمون اور دیگر اسلام پسندوں کو جس وحشیانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا، اس کے ردِ عمل میں ایک تکفیری سوچ وجود میں آئی۔ اس سوچ کی خود مصر میں دال نہ گلی اور خود اخوانیوں نے پر امن جدوجہد کا راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دی اور آج انہیں اپنی بروقت درست پالیسیاں اختیار کرنے پر فخر اور خوشی ہے، اس لیے کہ مصر میں آنے والی تبدیلی میں، جس کی تائید القاعدہ بھی کرتی ہے، اخوان کا بڑا حصہ ہے۔ لیکن سعودی عرب اور مصر میں پیدا ہونے والی اس سوچ اور آئیڈیالوجی کو، جسے اپنی سرزمین میں خاص جگہ نہیں ملی، ہمارے خطے نے بخوشی در آمدکرلیا اور یہ دیکھنے کی بھی زحمت گوار ا نہیں کی کہ اس آئیڈیالوجی کا ہماری اپنے برصغیر کی دینی جدو جہد کی روایت اور سوچ سے کتنا تعلق ہے۔ جزیرۂ عرب سے امریکیوں کے انخلا کا مشن درمیاں میں رہ گیا اور بات پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سعودی عرب اور مصر جہاں سے یہ سوچ اور شخصیات آئیں، آج وہ ملک اطمینان سے بیٹھے ہیں اور ہم سب کچھ بھگت رہے ہیں۔ ہم چونکہ ہر کوالٹی کے مال کے امپور ٹر ہیں، اس لیے آج جو لوگ اسامہ کو ایک ہیرو قرار دے کر ان کی شہادت پر احتجاج کررہے ہیں، وہی لوگ اسامہ کی بات نہ ماننے والے، اسے سعودی عرب کی شہریت سے محروم کرنے والے، اس کے اثاثے منجمد کرنے والے اور آخر میں اس کی لاش تک کو وصول کرنے سے انکار کرنے والے نظام کے حق میں بھی جلسے جلوس کررہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ بھی ہمارے ہیروزہیں جو موجودہ مسلمانوں حکومتوں کے خلاف خروج تک کو جائز کہتے ہیں اور اس نظام کے بھی حامی نظر آتے ہیں جو اپنے علما سے یہ کہلواتا ہے کہ کسی حکومت کے خلاف پر امن مظاہر ہ کرنا بھی گناہ ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد سہی، لیکن ہیں تو دونوں امپورٹڈ اور ہم ٹھہرے امپورٹڈ مال کے سب سے بڑے قدر دان اور خریدار۔
ہمارے اربابِ علم ودانش حضرات کے لیے یہ بات سوچنے اور ہمارے نوجوانوں کے ایک طبقے کو سمجھانے کی ہے کہ کب تک ہم دنیا بھر کے تنازعات کو اپنے ہاں درآمد کرتے رہیں گے؟ کیا خود اپنے پاس بجلی ، گیس وغیرہ کی طرح تنازعات کی بھی قلت ہوگئی ہے کہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم کہیں سے بجلی اور گیس درآمد نہیں کرپارہے تو کم از کم تنازعات درآمد کرکے اس خلا کو تو پورا کرلیں تاکہ بجلی اور گیس وغیرہ کی قلت سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کو اپنا ابال نکالنے کا کوئی ذریعہ توملے! تفنن بر طرف، واقعی ہمارے لیے یہ لمحۂ فکریہ ہے کہ بے تحاشا در آمد کی اس پالیسی نے ہمارے ملک کو کس حد تک پہنچا دیا ہے۔ کیااس ملک کی اس ناگفتہ بہ حالت کے اثراتِ بد دینی تعلیم ودعوت پر نہیں پڑیں گے؟
(بشکریہ ماہنامہ قیام، اسلام آباد)
’’حیات سدید‘‘ کے چند ناسدید پہلو (۱)
چوہدری محمد یوسف ایڈووکیٹ
(ہمارا تبصرہ کتاب ’’حیات سدید‘‘ پر ہے، زیر بحث شخصیت پر نہیں۔ کتاب میں زیر بحث شخصیت کا ہمیں پورا احترام ہے۔ البتہ سوانحی کتاب کے عنوان اور پھر اس پر تبصرہ کے لیے ہمارے عنوان سے شبہہ ہو سکتا ہے کہ ہم چوہدری نیاز علی کی حیات سے نا سدید پہلو پیش کر رہے ہیں۔ خاکم بدہن ایسا کیسے ممکن ہے۔البتہ کتاب کے مولف نے کتاب میں جو ناسدید سمت اختیار کی ہے، ہم نے اس پر گرفت کی ہلکی سی کوشش کی ہے۔ متوقع شبہہ کے ازالے کے لیے شروع ہی میں وضاحت لکھ دی ہے۔ مصنف)
ابتدائیہ
حیات سدید چوہدری نیاز علی خان کی سوانح ہے۔ یہ کتاب، حال ہی میں نشریات، ۴۰۔اردو بازار لاہور نے شائع کی ہے۔ ضخامت ۵۸۳ صفحات ہے۔ کتاب دیدہ زیب اور کافی معیاری کاغذ اور روز مرہ استعمال سے موٹے خط میں کمپوز کرائی گئی ہے۔ کتابت کی غلطیاں بھی کم ہیں۔ اس طرح یہ کتاب، مقامی مارکیٹ میں کافی غیر مقامی نظر آتی ہے۔ البتہ اگر اس میں مفصل اشاریہ شامل کر دیا جاتا تو یہ بین الاقوامی معیار کی برابری کرتی۔
کتاب کو تالیف کرنے والے کے ایم اعظم صاحب ہیں۔ یہ حضرت، جناب چوہدری نیاز علی خان مرحوم کے فرزندانِ ارجمندان میں سے ہیں۔ تالیف میں جناب نیاز علی مرحوم کی عظمت وعزیمت ، اپنے حقیقی امیج کے ساتھ سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولف اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اس پر کلام کرنا ہمارا ذمہ نہیں۔ البتہ اتنا کہنے میں کچھ حرج نہیں کہ ہمارے لیے تو اس کتاب سے چوہدری صاحب کی شخصیت کا مثبت تاثر اور بھی گہرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنا عرض کر دینا لازم ہے کہ کتاب کے مصنف نے کتاب کی ترتیب اس طرح سے کی ہے کہ اس سے بحیثیت مجموعی سید مودودی کا امیج مجروح ہو۔ انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ سید مودودی کا ان کے والد محترم انتہائی احترام کرتے تھے۔ وہ ان کو دارالاسلام (پٹھانکوٹ، بھارت)میں آنے کے لیے آمادہ کرنے کے کیے دوتین سال تک اصرار کرتے رہے۔ ان کے دل میں ان کی اس وجہ سے بھی قدر تھی کہ مولانا مودودی کے سوا کسی نے ان کے ہاں قیام کی دعوت قبول نہیں کی۔ کوئی بھی اپنی مجبوریوں سے نکلنے پر آمادہ نہ ہوا۔ فقط مولانا مودودی ہی تھے جو چوہدری نیاز علی خان کے خلوص سے مجبور ہوئے۔ انہوں نے اپنی ہر مجبوری پر قابو پایا اور کشتیاں جلا کر دارالاسلام پہنچے۔ یہ بد قسمتی ہی کہیے کہ قریباً آٹھ مہینے دارالاسلام میں قیام کے دوران صورت حال ایسی پیدا ہو گئی کہ دونوں بزرگوں نے تمام امور باقاعدہ طے اور بے باق کیے۔ معاملات میں کوئی امر طے طلب نہ چھوڑا۔ اس کے بعد مولانا لاہور سدھار گئے۔ مولانا مودودی کی آٹھ ماہ میں یہ دوسری نقل مکانی تھی۔ پہلی حیدرآباد دکن سے پٹھانکوٹ، دوسری پٹھانکوٹ سے لاہور۔
مولانا اس صورت حال میں کس ذہنی اذیت سے گذرے ہوں گے، اس کا اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ مگر مولانا مودودی بہت بلند عزم شخص تھے۔ انہوں نے اس دورِ اذیت کے حوالے سے کبھی چوہدری نیاز علی خان سے اپنے اختلافات پر ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ اس خاموشی کی وجہ مولانا کا مستحکم مزاج تھا۔ وہ وقتی حادثات سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہوں بھی تو ان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ علاوہ ازیں چوہدری نیاز علی خان کے خلوص کا بھی تقاضا تھا کہ اس اختلاف کو لوگوں میں پھیلا کر دو نہایت مخلص بزرگ اپنے آپ کے بارے میں منفی تاثر کو عام کرنے کا سبب نہ بنیں۔ اس کے علاوہ یہ وقتی علیحدگی تھی۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ اس اختلاف کے بعد بھی چوہدری نیاز علی، محض اپنے خلوص کی بنا پر مولانا کو واپس دارالاسلام لانے کے لیے پیچھا کرتے رہے اور آخر کار مولانا دوبارہ دارالاسلام آ گئے ۔ پھر مولانا قیام پاکستان تک چوہدری نیاز علی خان کے ساتھ دارالاسلام میں مقیم رہے۔ ان کے ما بین اس بار مکمل ہم آہنگی اور باہم مفاہمت قائم ہو چکی تھی۔ تقسیم ہند تک مولانا دارالاسلام میں قیام پذیر رہے۔ مولانا مودودی اور چوہدری نیاز علی خان نے، دارالاسلام سے اکٹھے ہی ہجرت کی۔ مولانا لاہور منتقل ہو گئے اور چوہدری نیاز علی خان دارالاسلام کے پاکستانی ایڈیشن کی جستجو میں مصروف ہوگئے۔ پہلی نقل مکانی جن اختلافات کے تحت ہوئی، ان کی کوئی اہمیت دوبارہ دارالاسلام میں منتقلی کے بعد باقی نہیں رہتی۔ سید مودودی اور چوہدری نیاز علی نے ان اختلافات کو اپنے سینوں میں مستور رکھا۔ مصنف کے لیے اپنے والد کے دوست اور مہمان کے طور پر مولانا مودودی کا احترام واجب تھا مگر جس باب کی پردہ داری مصنف کے والد اور سید مودودی نے پورے اہتمام سے کی، مصنف نے پوری کوشش سے ان اختلافات کو پون صدی گزرنے کے بعد سامنے لانے کی جستجو کی ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی اہمیت۔ یہ سب کچھ کیسے کیا گیا، کتاب کے طائرانہ نظر ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، ہم اس بارے میں تفصیل سے پہلے پیش لفظ کو لیں گے۔
جناب مجید نظامی کا پیش لفظ
یہ پیش لفظ جناب مجید نظامی کی طرف سے ہے۔ وہ کتاب کے صفحہ نمبر ۱۴ پر لکھتے ہیں:
’’مولانا مودودی کی علامہ اقبال سے قربت کے قصے گھڑے گئے تھے حالانکہ چوہدری نیاز علی خان کے وقفِ دارالاسلام میں علامہ اقبال نے جامعہ الازہر سے ایک عالم بھجوانے کی درخواست کی۔ درخواست کو بوجوہ پذیرائی نہ ملی تو علامہ نے چوہدری غلام احمد پرویز سے دارالاسلام کے امور سنبھالنے کو کہا، ان کو قائد اعظم نے اجازت نہ دی۔ علامہ کی سب سے پہلی ترجیح تو علامہ اسد تھے، ان کے آڑے ان کی مصروفیات آ گئیں۔ آخر میں چوہدری نیاز علی خان نے مولانا مودودی کا نام دیا تو علامہ نے اتفاق کیا۔ علامہ نے مولانا مودودی کو ملا قرار دیا تھا جو بادشاہی مسجد کی امامت کے لیے موزوں ہیں۔ تاہم مولانا کے علامہ کے بارے میں کبھی اچھے خیالات اور جذبات ہوا کرتے تھے پھر دھوپ اور سائے کی طرح بدلتے رہے۔
’’مولانا مودودی قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھے، اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ بہت سے اس کتاب میں درج کر دیے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی آج اگر مولانا کو تحریک پاکستان کا رہنما اور پاکستان بنانے والی تیسری شخصیت قرار دے تو یہ حقائق کو مسخ کرنے کی دانستہ کوشش ہے، جس سے شاید جماعتیوں کے سینے میں کچھ ٹھنڈ پڑ جاتی ہو لیکن یہ قوم کو گمراہ کرنے کی ایک لا یعنی کوشش ہے۔ ایک مرتبہ مولانا مودودی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ، آپ نے پاکستان کی مخالفت کی۔ اب کہتے ہیں سیاست یوں کریں (اور یوں نہ کریں)۔ آپ کو سیاسی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں پہنچتا۔ جماعت کے لیے میرا آج بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ فلاحی اور رفاہی کام کرے، سیاست اس کے بس کا روگ نہیں۔ کتاب کے مصنف نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ تاہم قاری پر اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے، فیصلہ اس کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔‘‘
مجید نظامی ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں۔ وہ صاحبِ رائے شخص ہیں۔ رائے کے اظہار میں ہمیشہ بلند آہنگ واقع ہوئے ہیں۔ بڑے سے بڑے مقتدر کے سامنے انہوں نے اس کا بر ملا اظہار کیا ہے۔ یہ ان کی ایسی خوبی ہے جو کم از کم آج کل تو بالکل نایاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا، ان کی رائے ہے۔ مگر یہ رائے اب مولانا سے نجی ملاقات میں اظہار سے آگے نکل کر ایک کتاب کے پیش لفظ کا حصہ بننے کے بعد، پبلک حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ لہٰذا اس کا سنجیدہ جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست پاکستان میں قیام پاکستان سے اختلاف ہی نہیں بلکہ کسی معاملے میں اختلاف کو برداشت تک نہیں کیا جاتا۔ مولانا مودودی کی جانب سے قیامِ پاکستان کی مخالفت اور اس بنا پر مجید نظامی صاحب کے کہنے کے مطابق سیاست سے باز رہنے کے مشورے کے بارے میں تو ہم بعد میں عرض کریں گے، البتہ سیاستِ پاکستان میں عدم روا داری اور عدم برداشت کے رویوں کی شروعات کو سامنے لائیں گے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ان شروعات پر مملکت کی تعمیر جس رخ پر چلی گئی ہے، اس کا اندازہ ہو سکے۔ اس سے اس مسئلے کی نزاکت کا بھی اندازہ ہوسکے گا۔
البتہ شروع ہی میں یہ عرض کر دینا لازم ہے کہ مسلم لیگ پاکستان کی منہ بولی ماں بنتی ہے۔ اپنی اس حیثیت میں وہ پاکستان کی واحد وارث چلی آ رہی ہے۔ مسلم لیگ کی یہ حیثیت، پاکستان کے خالق جماعت، کی وجہ سے عمومی طور پر تسلیم کی گئی ہے، البتہ ایک محدود نقطہ نظر اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ کو خلاق پاکستان یا خالقہ پاکستان ہونے کے باوجو، داپنی اہلیت ثابت کرنا پڑے گی۔ اگر یہ اپنی اہلیت، کار کردگی سے، ثابت نہ کر سکی تو اس کے دعوے کا حقیقی جواز ختم اور اس کی حیثیت غصب میں بدل جائے گی۔ یہی بات سید حسین شہید سہر وردی کا منشا تھا۔ اس کے نتیجے میں سہروردی کے ساتھ کیاہوا، ان کی خدمات کو کس طرح گہنایا گیا، یہ ذمہ دارانِ مسلم لیگ پر ایک لمبی فرد جرم ہے۔ اتنا تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ سہر وردی صاحب ۱۹۳۶ء کے بنگال اسمبلی کے انتخابات میں دو نشستوں سے منتخب ہوئے جب کہ خواجہ ناظم الدین اپنی نشست ہا ر گئے۔ سہر وردی نے ایک نشست خالی کی اور اس نشست سے خواجہ ناظم الدین کو منتخب کرایا۔ سہر وردی متحدہ بنگال کے پارلیمانی قائد اور وزیر اعلی منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان تک وہ اس منصب پر فائز رہے۔ بنگال تقسیم ہوا اور پاکستان بنا تو انہوں نے اس منصب کا چارج ہندی بنگال کے پارلیمانی قائد کو منتقل کیا ۔ پاکستان بنا تو سہروردی نے ہندی بنگال سے پاکستانی بنگال آنا چاہا تو خواجہ ناظم الدین نے ان پر پاکستانی بنگال آنے پر پابندی لگا دی۔ ان واقعات کی تفصیلات کے لیے سید حسین شہید سہروردی کی یادداشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ یادداشتیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ۲۰۰۹ء میں چھپی ہیں۔
خواجہ ناظم الدین کی طرح لیاقت علی خان بھی مسلم لیگ میں مرد ثانی کے مرتبے پر رہے۔ ان کا رویہ بھی جناب سہروردی کے بارے میں اسی قسم کا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ناظم الدین کی جانب سے سہروردی کو بنگال میں داخلے سے روکنا اپنے طور پر نہ ہو وزیر اعظم لیاقت علی خان کے اشارے پر ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ناظم الدین اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس طرح کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ مولاے اعلیٰ کی بات کو ٹالنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ بعد ازاں حسین شہید سہروردی کی قیام پاکستان کے لیے خدمات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ان پر غداری کا الزام تک لگایا گیا ۔ ایوب خان تک معاملات پہنچتے پہنچتے تو زیادہ ہی بگڑ چکے تھے۔ ایوب خان خوشامد اور سازش کی بیساکھیوں پر چل کر اقتدار کو غصب کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر وہ خلا میں رہ رہے تھے۔ لیاقت اور ناظم الدین بہر حال ایک سیاسی پس منظر رکھتے تھے۔ ایوب خان ایسے پس منظر سے یکسر محروم تھے۔ ان کے پاس تو سہر وردی سے گلو خلاصی کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ تفصیلات کا موقع نہیں۔ ہم یہاں جناب مجید نظامی کی ایک گفتگو کا مختصر اقتباس درج کر کے بات بڑھائیں گے:
’’مجید نظامی کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایسی اموات پر سوالیہ نشان موجود ہیں۔ ۔ ۔ ایسی اموات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون کس طرح موت کے تاریک راستوں کا حصہ بن گیا۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم سید حسین شہید سہروردی بیروت میں مارے گئے۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی کے جلسے میں مارے گئے اور ان کے قاتل سید اکبر کو پولیس پہرے میں مار دیا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم گورنر جنرل کی حیثیت سے شدید علالت کے باعث کوئٹہ سے کراچی آ رہے تھے تو وزیر اعظم لیاقت علی خان انہیں ریسیو کرنے نہیں آئے، جو ایمبولینس ان کے لیے بھیجی گئی تھی ائیر کنڈیشنر کے بغیر تھی اور اس کا انجن راستے میں فیل ہو گیا وہ سڑک کے کنارے کھڑی رہ گئی۔ اسی طرح ضیا الحق ہوا میں مارے گئے، جس حادثہ میں امریکہ کا سفیر بھی مارا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ضیا الحق کیس میں جنرل اسلم بیگ زندہ ہیں مگر وہ روشنی نہیں ڈالتے۔ ۔ ۔ لہذا اس قسم کی اموات پسِ پردہ اندھیروں میں چلی جاتی ہیں۔ ۔ ۔ مادر ملت کو کس نے مارا۔ یہ ابھی تک راز ہی ہے لیکن گذشتہ روزایک پیر پختہ کار پیرزادہ شریف الدین صاحب کا بیان نظر سے گزرا کہ محترمہ کو ان کے پشتو سپیکنگ ملازم نے ڈنڈوں سے مارا تھا۔‘‘ (’’جب تک زندہ ہوں، مجید نظامی کی کہانی ‘‘ مرتبہ عائشہ مسعود، شائع کردہ فیکٹ پبلیکیشنز اسلام آباد صفحہ نمبر ۶۶)
سہر وردی کو پاکستانی سیاست میں پابند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تحریک پاکستان میں ان کی خدمات لیاقت علی اور ناظم الدین سے بہر حال زیادہ تھیں۔ لیاقت علی کو تو قائد اعظم کا دست راست ہونے کا edge حاصل تھا۔ سہر وردی کا سیاسی کردار بظاہر بنگال تک محدود تھا مگر حقیقت میں وہ مسلم لیگ میں بر صغیر کی سطح کے قائد تھے۔ تحریک پاکستان میں ان کی خدمات تاریخ کا حصہ ہو گئی ہیں۔ اس کے باجود ان کو سیاست پاکستان سے باہر نکالنے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ پا کستان کی سیاست کے مزاج کی تشکیل میں بنیادی کجی کی وجہ سے ہی تھا۔ ہمیں شک پڑتا ہے کہ حیات سدید کے پیش لفظ میں مجید نظامی کی مندرجہ بالا سطور کا کچھ تعلق اس کجی سے بھی ہے۔ اگرچہ مجید نظامی کسی کے حریف نہیں۔ جب کہ لیاقت علی خان تو واضح طور پر سہر وردی مرحوم کے حریف تھے۔
اس کجی کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ عوامی سطح پر اور صلاحیت کے اعتبار سے طاقت ور حریف کو نیچا دکھانے کے لیے، اس طرح کے منفی حربے اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کی پالیسیاں اختیار کی جائیں۔ ایسی پالیسیاں جن کا پبلک کی سطح پر جواز پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھیں لیاقت علی خان نے اس مملکت خدا داد کے ساتھ کیا کیا۔ ان کا سب سے بڑا ’’کارنامہ ‘‘ ایوب خان کو سپاہ پاکستان کا سربراہ مقرر کرنا تھا۔ ایوب خان نہایت حریص شخص تھا۔ قائد اعظم اس کو بے حد نا پسند کرتے تھے اور اسے فوج سے فارغ کر دینا چاہتے تھے۔ وہ مہاجرین کی پر امن اور محفوظ منتقلی میں اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ رہا۔ اس کے باوجود لیاقت علی خان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس میں ایوب خان کا خوشامدی رویہ بار آور ہو کر رہا۔ یہ تقرری میرٹ کے خلاف تھی۔ اس کے نتائج سے آج تک ملک نہیں نکل سکا۔ تاریخ پاکستان کی تمام تر سیاہی اسی ایک خلاف میرٹ فیصلے سے شروع ہوئی۔
جناب لیاقت جھرلو انتخابات کے موجد ہوئے۔ خارجہ پالیسی میں امریکی غلامی کے بیج بونے کا کریڈٹ بھی جناب لیاقت علی خان ہی کو جاتا ہے۔ کشمیر میں یکم جنوری ۱۹۴۹ء کو جنگ بندی قبول کرنے کے بعد،کشمیر محاذ پر لڑنے والے بہادر افسروں کو چن چن کر عتاب کا نشانہ بنایا گیا۔ پنڈی سازش کیس بظاہر ایک ڈرامہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر جماعت کی سیادت اور حکومت کی سربراہی کو اپنی ذات میں جمع کرنے کی بدعت بھی جناب لیاقت علی نے ایجاد کی۔ ان کو مزید خدمات کا موقع نہ ملا اور شہید ہو گئے۔
اس مرحلہ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مملکت پاکستان کی سیاست کی یہی ادائیں، صف اول کے زعمائے پاکستان کے شایان شان تھیں۔ یہ نازک ادائیں کیا کوئی مستحکم سیاسی ماحول تشکیل دے سکتی تھیں۔اس پس منظر میں ہم جناب مجید نظامی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کو یہ مشورہ کہ وہ سیاست سے باز رہیں، اس لیے کہ وہ قیام پاکستان کے مخالف رہے ہیں۔ اس میں معقولیت کا کون ساپہلوہے۔
مولانا مودودی اور جماعت اسلامی نے قیام پاکستان کی مخالفت کی یا نہیں کی۔ اگر کی بھی تو وہ کسطرح اور قدر۔ اس کی نوعیت کیا تھی۔ اس کی تفصیل ہم بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قیام پاکستان کی مخالفت کی بنیاد پر پاکستانی شہریوں کے سیاسی حقوق کا تعین ہو گا۔ قائد اعظم تو اس پہلو سے مسلم اور غیر مسلم تک کے امتیاز کو بھی خاطر میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ ترقی پسند حلقے قائد کی تقریر کو اپنے مفاد میں تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے اسے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں پر کلہاڑے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا منشا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ مسلمانوں اور پاکستانی شہریوں کے حقوق کے بارے میں قیام پاکستان کی حمایت یا مخالفت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے قائد اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔
قائد کے رہنما اصول
قائد اعظم نے ۱۱۔ اگست ۱۹۴۷ء کو دستور ساز اسمبلی سے اپنے صدارتی خطبہ میں ارشاد فرمایا:
’’مجھے معلوم ہے کہ ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہندوستان کی تقسیم سے متفق نہیں ہیں اور بنگال و پنجاب کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں ۔ لیکن اب جب کہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اسے قطعیت حاصل ہونے کے بعد قبول کر لیا گیا ہے۔ ہم سب اس کے پابند ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم تقسیم کے اس معاہدے پر ایمان داری اور با وقار طریقے سے عمل کریں۔ تقسیم بہر صورت ہونا تھی۔ ہندوستان اور پاکستان، دونوں طرف ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے متفق نہ ہوں۔ جو اسے پسند نہ کریں۔ مگر میرے خیال میں مسئلے کا کوئی اور حل ممکن نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تاریخ کا فیصلہ تقسیم کے حق میں ہو گا۔ لیکن یہ تجربہ سے واضح ہو گا۔ یہ واضح ہے متحدہ ہندوستان کا کوئی تصور عملی طور پر ممکن نہیں تھا۔ میرے فہم میں اس پر اصرار کا نتیجہ مکمل تباہی ہوتا۔ میری رائے درست ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے فیصلہ کا انتظار کرنا ہو گا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں عوام الناس خاص طور غریب لوگوں کی بھلائی کے لیے یکسوئی سے کام کرنا ہو گا۔ اگر ہم ماضی کو فراموش کر کے باہم تعاون کے جذبے سے کام کریں گے۔ اس بات سے کوئی واسطہ نہ رکھیں کہ کوئی آپ سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ کسی کا کون سا رنگ ہے۔ ذات کیا ہے اور وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں اول و آخر یہ دیکھنا ہو کہ وہ مملکت کا شہری ہے۔ وہ برابر کے حقوق اور مراعات کا حق دار ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ترقی اپنے عروج پر ہی نہیں بلکہ اس کی ایک انتہا کے بعد دوسری انتہا سامنے ہو گی۔ ۔ آپ مکمل طور پر آزاد ہیں۔ اپنے مندروں، مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں میں جانے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہو گی۔ ۔ ۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس مثالی صورت حال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ کوئی شخص بھی مذہبی بنیاد پر تعصب نہیں برتے گا۔ کوئی متعصب ہندو رہے گا اور نہ متعصب اور تنگ نظر مسلمان۔ میرا منشا یہ نہیں کہ میں مذہبی حوالے یہ بات کر رہا ہوں۔ مذہب تو ہر ایک کا شخصی معاملہ ہے۔ میرا منشا سیاسی لحاظ سے مملکت کے ایک شہری کے طور پر ہے۔ جہاں میرا تعلق ہے میں ہمیشہ بے لاگ انصاف پر کار بند رہوں گا۔ کسی تعصب، وابستگی کے بغیر۔ کامل عدل اور غیر جانب داری میرا طریقہ ہو گا۔‘‘ (Jinnah Speeches as Governor General 1947-48 page 8-10)
کیا مجید نظامی سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ قائد اعظم کے اس واضح فرمان کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کبھی اقتدار کے ایوانوں کے لطف اٹھا آئے ہوتے تو ہم ان کی بات کا نوٹس ہی نہ لیتے۔ ایک صاحب کردار اور عظیم صحافی کے طور پر، ان کے پیش لفظ سے مجھے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ ایک عظیم شخصیت کی سوانح کا پیش لفظ لکھتے ہوئے جناب نظامی کا یہ اندازِ تحریر، نرم سے نرم الفاظ میں غیر ذمہ دارانہ ہے۔ در اصل سوچنے کا یہی انداز ہے جس نے ہمارے ہاں سیاسی ماحول اور کلچر کی تعمیر کی ہے۔ ایسی تعمیر میں خرابی کی یہی صورت مضمر ہے۔ اب تو یہ تعمیر اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ اب عمارت بوسیدہ ہوچکی ہے اور اس نے گرنا شروع کر دیا ہے۔ مگر کتنے بڑے نقصان اور تباہی و ہلاکت کے بعد، اس کا قصہ بیان کرنے لگیں تو قلم تھک جائے گا۔ قرطاس ختم ہو جائے گا اور لکھنے والے کی ہمت جواب دے جائے گی۔ ایک دو برس کی بات نہیں، زائد از نصف صدی کا معاملہ ہے۔
اجارہ دارانہ رجحان
تحریک پاکستان میں شرکت کی بنیاد پر اجارہ داری کا رجحان، شاید قائد زندہ رہتے تو رواج نہیں پا سکتا تھا۔ اگر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر تقرری میں سب سے بڑی آبادی کے نمائندے کے طور پر حسین شہید سہر وردی کو جگہ دی جاتی تو یقینی طور پر پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ لیاقت علی کی تقرری کن حالات میں ہوئی۔ کون سی مصلحتیں اس کا محرک ہوئیں، پردہ تاریخ میں مستور ہیں۔ اس کے بعد اجارہ دارانہ کردار پوری طرح چھا گئے۔ جناب لیاقت علی خان اپنے پونے چار سالہ وزارت عظمے کے دور میں ان رجحانات کو اتنا مستحکم کر گئے کہ بعد میں ان کو کوئی چیلنج کرنے والا سامنے ہی نہ آیا، آیا بھی تو کسی نے اس کو اہمیت ہی نہ دی۔ نتیجہ کیا نکلا ؟
یاران بزم !صبح ِ وطن سی عزیز شے
کیوں کر ہوئی ہے شام غریباں نہ پوچھئے
ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، مشیر کاظمی کا نوحہ درج کر دیتے ہیں۔ یہ نوحہ یوم اقبال پر یونیورسٹی سینٹ ہال میں، میں نے خود بھرے مجمع میں سنا۔ وہ بھی رو رہے تھے اور مجمع بھی رو رو کر نڈھال ہو رہا تھا:
پھول لے کر گیا، آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں
قبر سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں
قبر پر قوم ساری تھی نوحہ کناں، آنکھ سے آبگینے تھے پھوٹے ہوئے
چند ہاتھوں میں گلشن کی تصویر تھی، چند ہاتھوں میں آئینے ٹوٹے ہوئے
سب کے دل چور، سب ہی مجبور تھے، بیکسی وہ کہ تابِ نظارا نہیں
شہرِ ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے
خوں میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روحِ قائد بھی تھی سر جھکائے ہوئے
کہہ رہے تھے سبھی، کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارانہیں
سرنگوں قبر پہ تھا منارِ وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدارِ وطن
آج کے نوجواں کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ حصارِ وطن
جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، ان کی تصویر ہے، یہ منارا نہیں
کچھ اسیرانِ گلشن تھے حاضر وہاں، کچھ سیاسی مہاشے بھی موجود تھے
چاند تارے کے پرچم میں لپٹے ہوئے، چاند تاروں کے لاشے بھی موجود تھے
میرا ہنسنا تو پہلے ہی اک جرم تھا، میرا رونا بھی ان کو گوارا نہیں
کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شیر تھا ایک میں، ارضِ بنگال کا
شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہیں تھا میں ذہنِ اقبال کا
ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں
اس چمن کے تھے بلبل ستائے ہوئے،اس چمن کے بھی بلبل ستائے ہوئے
آج شاخ و شجر، رنگ بوئے چمن، باغبانوں سے ہیں خوف کھائے ہوئے
وہ نہ زندوں میں ہیں اور نہ مردوں میں ہیں، ایسی موجیں ہیں جن کا کنارا نہیں
وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی، میرے خونِ جگر سے بنائی گئی
قوم کی ماؤں بہنوں کی جو آبرو، میرے خون جگر سے سجائی گئی
موڑ دو آبرو، یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں
یقین کیجیے، اگر مشیر کاظمی لاہور میں علامہ اقبال کی قبر کے بعد، یہی پھول لے کر، کراچی میں قائد کے مزار پر بھی جاتے تو یہی صدا آتی اور یہی نوحہ بلند ہوتا۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر وہ حمید نظامی، چوہدری نیاز علی یا مولانا مودودی کی نشان ہاے خاک پر جا کر یہ نوحہ پڑھتے تو یقینی طور پر یہی صدائیں آتیں۔ لیکن یہی پھول لے کر اگر مشیر کاظمی تو کیا، کوئی بھی لیاقت علی خان، شیخ مجیب الرحمان، ممتاز محمد دولتانہ، ذوالفقار علی بھٹو، ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق جیسے وارثان اقتدار کی قبر پر جاتے تو کوئی صدا بلند ہوتی؟ ہوتی تو وہ یہی ہوتی یا اس سے مختلف ہوتی؟ اجارہ دارانہ رجحانات کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ دور مشرف میں ماؤں بہنوں اور نوخیز پھولوں تک کو فروخت کر دیا گیا۔
اس کے تذکرے کی تفصیل سے بچتے ہوئے عافیہ صدیقی کی امریکی عدالت کے چوراسی سال کی سزائے قید پر لکھی ہوئی ایک نظم نقل کر کے حیات سدید کی طرف آتا ہوں۔ یہ نظم ایک غیر معروف شاعر، ناصر بشیر کے احساساتِ خونچکاں ہیں۔ مصرِ عِ اول نظم کا عنوان ہے،
میرے منصف نے عجب فیصلہ لکھا ہے مرا
ایک میں ہی نہیں، حیران زمانہ ہے مرا
شہر والو! مجھے حیرت سے نہ دیکھو ایسے
یہ مرے اشک نہیں، خونِ تمنا ہے مرا
روح یہ پوچھتی پھرتی ہے گلی کوچوں میں
مجھ کو بتلاؤ! بدن کتنے میں بیچا ہے مرا؟
دیکھتی رہتی ہوں ،بیٹھی در و دیوارِ قفس
دل رہا ہونے کی امید پہ ہنستا ہے مرا
آج بھی قفل پڑا ہے، درِزنداں پہ وہی
آج بھی دل ، کسی آہٹ کو ترستا ہے مرا
موج در موج مری پیاس بڑھی جاتی ہے
یہ الگ بات ،مری آنکھ میں دریا ہے مرا
ہیں میرے اہل وطن میرے لیے محو دعا
کس بلندی پہ ،مقدر کا ستارہ ہے مرا
سرخ رو ہو کے کبھی، اپنے وطن آؤں گی
میں ہوں سچائی، مرے ساتھ زمانہ ہے مرا
حیاتِ سدید میں جنابِ مجید نظامی کے پیشِ لفظ میں درج، جملوں کو دیکھ کر ہم نے ابتدائی تاثر کے طور پر جو کچھ عرض کیا ہے، اس سے آگے ذرا اس پیش لفظ پر کھل کر گفتگو کی ضرور ت ہے۔ البتہ اتنا شروع ہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ حیات سدید ہے کتابِ سدید نہیں۔ استاذی و عزیزم پروفیسر سلیم منصور خالد اس کتاب کی تقریب رونمائی میں مولف کی تقریر کے حوالے سے قولِ سدید کی تلاش میں خواہ مخواہ سر گرداں ہوئے(نوائے وقت ۱۴۔تا ۱۶ نومبر ۲۰۱۰)۔ کتاب میں مرحوم و مغفور چوہدری نیاز علی خان کے حوالے سے خطوط اور دیگر دستاویزات تو قولِ سدید کا صحاح ہیں مگر جناب مولف نے جہاں کہیں خود سے کچھ لکھا ہے یا اس میں دوسروں کی جو تحریریں، بھرتی کی صورت میں جمع کی ہیں وہ خالص کھوٹ ہے۔ اگرچہ جناب مجید نظامی پیش لفظ میں یہی فرماتے ہیں کہ کے ایم اعظم صاحب نے ’’دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی‘‘ کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کتاب کو بغور پڑھنے کا کسی کے پاس وقت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ دودھ اور پانی کو الگ الگ کرتے ہوئے جناب کے ایم اعظم صاحب نے خود کتنا پانی شامل کیا اور یہ پانی شامل کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ پانی جوہڑ سے لے رہے ہیں یا نہر سے۔
جناب کے ایم اعظم کی صوابدید ہے۔ ہم اس صورت حال کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ چوہدری نیاز علی مرحوم نے اپنی عمر بھر کی کمائی سے، جمال پور ضلع پٹھانکوٹ (بھارت) میں دارالاسلام تعمیر کیا۔ متحدہ ہند کی تقسیم کے موقعہ پر، دارالاسلام کے موسس و واقف، اس ٹرسٹ کو پٹھانکوٹ میں چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان آ کربھی دارالاسلام کے تصور نے ان کو بے چین رکھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا دوسرا ایڈیشن تعمیر کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں میں انہوں نے سرکار مدار میں اپنے استوار رابطے آزمائے۔ سرخ فیتے کو ناپنے میں ہر ممکن جادہ پیمائی کرتے ہوئے، انہوں نے ’’کوہ کن‘‘ جیسے مراحل سر کیے۔ تب جا کر اس تصوراتی نقشے میں عملی رنگ دکھائی دینے لگا۔ وہ دارالاسلام اول (پٹھانکوٹ) میں سید مودودی اور ان کے کچھ ساتھیوں کو اقامت پر مائل کر چکے تھے مگردارالاسلام دوئم (جوہر آباد) میں اقامت کے لیے، کوئی نمایاں شخص ان کی دستبرد میں نہ آ سکا۔ اس مقصد کے لیے تگ و دو میں انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔
خوابوں کی عملی تعبیر بے نتیجہ ہونے پر جب کسی مشنری شخص کے قلب و ذہن، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو زندگی موت سے زیادہ بد تر اور مایوسی کا شکار ہوجاتی ہے۔ چودھری نیاز علی خان کو تو ان مراحل سے پار ہوتے ہوئے قبر کے لیے دو گز جگہ تو نصیب ہو گئی۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی قبر کو ان کی اولاد نے بے نشان کر دیا۔ اس کا گلا جناب کے ایم اعظم صاحب نے کتاب میں بھی کیا ہے۔ وہ یہ گلا کس سے کر رہے ہیں، مولانا مودودی سے، جماعت اسلامی سے یا اپنے برادر بزرگ سے یا اپنے آپ سے، اس بارے میں مصنف نے چپ سادھ لی ہے۔ حالانکہ اس پہلو سے ان کو اپنے والد کے جائز وارث ہونے کے ناطے سے کتاب میں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی۔
آئندہ صفحات میں ہم ’’حیاتِ سدید‘‘ پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
(جاری)
علامہ شبیر احمد ازہر میرٹھیؒ (۱۹۲۳ء۔۲۰۰۵ء)
ڈاکٹر محمد غطریف شہباز ندوی
صدیاں ہوتی ہیں، وقت کے ایک عظیم عالم (ابن تیمیہؒ ) کی وفات پر دمشق کے میناروں سے آواز بلند ہو ئی تھی: الصلاۃ علی ترجمان القرآن (ترجمان قرآن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی)۔ ۲۴؍ جنوری ۲۰۰۵ء کو ہندوستان کو بھی حق تھا کہ اس کے گوشہ گوشہ سے بھی یہی آواز بلند ہوتی کہ وقت کے ابن تیمیہ، ترجمان قرآن وسنت، محدث عصر علامہ شبیر احمد ازہر میرٹھیؒ نے اسی دن دنیا کو خیر باد کہا۔ ان کی وفات پر ایک عظیم علمی روایت کا خاتمہ ہوا۔ یہ کو ئی معمولی حادثہ نہ تھا کہ اس پریوں ہی گزر جایاجائے، لیکن مسلمانان ہند اپنے علمی وفکری زوال وانحطاط کے جس مقام پر ہیں، وہاں یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلاکہ کیا ہوگیا۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک عہد فراموش دور میں جی رہے ہیں جہاں پرہر چیز کو بھلا دیاجاتاہے، تاہم عوام تو عوام، علما ، ارباب مدارس، اسلامی تحریکوں اور اسلامی علوم کے طلبہ کا ایسے گوہر نایاب اور متاع بے بہا کے بارے میں تجاہل، تغافل اور ناآشنائی کا یہ رویہ جس کا ایک عمومی مشاہدہ کیا گیا، ایک ملی المیہ اور ہماری علمی تاریخ کے ایک عبرت ناک باب سے کم نہیں۔ خصوصاً ایسے دور میں جہاں درباری مدعیان علم اور مختلف فرقوں، جماعتوں ، تنظیموں اور اداروں کے قائدین پر زور سیمینار ہوتے ہیں اور اخباری شہرت رکھنے والے ہما وشما پر خصوصی گوشے اور نمبرات شائع کیے جاتے ہیں!!
خاندان :عہد اسلامی میں شمالی ہند میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان میں برہمنوں وراجپوتوں اور گوجروں سے نکلی ہوئی بہت سی برادریاں بھی ہیں۔ انھی میں ایک چودھری برادری بھی ہے جن کاآبائی پیشہ کاشتکاری ہے ۔موضع توڑی ضلع غازی آباد میں سکونت پذیر اسی برادری کے ایک متوسط درجہ کے خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے دادا ایک نیک دل اور سیدھے سادے دیندار کسان تھے جنہوں نے خود تو معمولی دینی تعلیم پائی تھی لیکن اپنے بچوں کو اچھی دینی و قرآنی تعلیم سے آراستہ دیکھنے کی بڑی تمنا اور آرزو تھی ۔والد حافظ بشیر احمد علاقہ کے انتہائی جید حافظ وقاری تھے جن کے حفظ کا دور دور تک شہرہ تھا۔ والدہ زبیدہ خاتون بھی نہایت عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ اوپر کے شجرہ کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ نہ خودمولانا نے کہیں تذکرہ کیا اور نہ وہ شجروں اور نسبتوں وغیرہ کے وہ قائل تھے کہ بقول امام الہند مولاناابو الکلام آزادؒ :
’’اسلا م نے ساری نسبتوں اور ا متیازوں کو مٹا کر صرف اپنی ایک نسبت نوع انسانی کو عطا کی اور اس نسبت سے بڑھ کر اور کون سی نسبت ہوسکتی ہے جس کی ایک مسلمان کو تلاش ہو؟ انسان کے لیے معیار شرف جوہر ذاتی اور خود حاصل کردہ علم وعمل ہے نہ کہ اسلاف کی روایت یا رینہ اور نسب فروشی کا غرور باطل ۔ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے نسب سے ہمارے خاندان کے شرف رفتہ کے محتاج ہوں! ارباب ہمت نے ہمیشہ اپنی راہ خود نکالی ہے۔‘‘ (تذکرہ صفحہ ۲۶)
تعلیم و تربیت
مولانا شبیر احمد ازہر نے کم سنی میں ہی قرآن پاک حفظ کرلیا تھااور ۱۷،۱۸سال کی عمرمیں ہی علوم دینیہ کے اکتساب سے فارغ ہوگئے تھے۔ اس وقت کے مروجہ درس نظامی کے پورے کورس، جو ۱۲سال کو محیط ہوتا تھا، کی تکمیل انھوں نے صرف ۵سال میں کرلی تھی۔ ان کے خاص استاد مولانا شاہ اختر خان امروہوی تھے جن کے خاص استاد کانام بھی شبیر احمد تھا اورجو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے شاگرد بھی تھے۔ شاہ اختر خان ؒ نے ان کو پورا قرآن صرفی و نحوی ترکیب کے ساتھ پڑھایا اور حدیث و فقہ کی منتخب کتابیں خصوصی طور پر پڑھائیں۔اپنے اس شاگرد پر ان کی خصوصی نظر عنایت تھی۔وہ اپنے اور شاگرد دونوں کی مناسبت سے کہا کرتے کہ’’ شبیر سے لیا اور شبیر کو دے دیا‘‘۔ مروجہ علوم کی تکمیل شاہ اختر خان صاحب سے کرنے کے بعد انھی کی ایما پر جامعہ تعلیم الدین ڈھا بیل گجرات تدریس کے لیے جانا ہوا۔ وہا ں انتہائی کم عمر ی کے باوجو د اونچے درجوں کی کتابیں پڑھائیں۔ کچھ عرصہ بعد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ؒ ہندوستان آئے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث وصدر مدرس بنائے گئے تو استاد کے اشار ہ پر ڈھابیل سے لوٹے اور دیوبند سے دورۂ حدیث کیا۔ وہاں خاص اساتذہ میں شیخ الادب مولانا اعزاز علی امروہویؒ ، مولانا فخرالحسنؒ اور حضرت مدنیؒ تھے۔
تدریسی خدمات
دیوبند سے سندفضیلت کے حصول کے بعد آپ نے مختلف مدارس اور اداروں میں علوم اسلامیہ کی تعلیم وتدریس کا آغاز کیا اور تقریباً ۷۵سال کی عمر ہونے تک ہندوستان کے بڑے اور اہم مدارس میں تدریس کی خدمات انجام دیں۔ ۳۰ سال سے زائد عرصہ تک صحیح بخاری پڑھائی۔ ان مدراس اور اداروں میں جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل، جامعہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ، مدرسۃ الاصلاح سرائے میراعظم گڑھ، ریاض العلوم دہلی، جامعہ امدادیہ مراد آباد ،نورالاسلام صدرمیرٹھ، جامعہ ندوۃ السنہ کیرالا اور جامعۃ الصالحات رامپور، مدرسہ عربیہ چلہ امروہہ اور دوسرے بہتیرے مدارس اور ادارے شامل ہیں۔ علوم اسلامیہ، قرآن وحدیث، تفسیر، اصول، فقہ، اصول فقہ، فلسفہ ومنطق اور ادب عربی، بلاغت اور علم عروض میں بھی زبردست تبحر حاصل تھا۔ ساتھ ہی طب یونانی، بنوٹ، گھڑسواری وشمشیر زنی میں بھی انھیں مہارت وحذاقت تامہ حاصل تھی۔ یادداشت اور قوت استحضار اتنی تھی کہ جو چیزیں ۵۰، ۶۰ سال پہلے پڑھی تھیں، وہ بلا کتاب دیکھے پڑھادیا کرتے تھے۔ ابتدائی درجوں کی تمام کتابیں انھوں نے خود راقم کو پڑھائیں، چنانچہ ان کے اس کمال کا خوب تجربہ ہوا۔ یوں تو تمام علوم کا استحضار تھا لیکن علو م قرآن اور علوم سنت سے خصوصی شغف تھا۔ یہی دونوں زندگی بھر اوڑھنا بچھونا رہے۔
علمی خدمات
اردو عربی اور فارسی لکھنے اور بولنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ عربی واردو بے حد روانی سے اور بے تکان لکھتے چلے جاتے۔ انھوں نے زندگی کے آخری دن تک لکھا۔ ان کے گہربار قلم سے کتاب وسنت کے علوم سے متعلق درج ذیل شاہ کار کتابیں نکلیں:
۱۔ تفسیر مفتاح القرآن مکمل اردو جس کے سورۂ آل عمران تک صرف ۶؍اجزائابھی تک طبع ہوئے ہیں، باقی مسودات کی شکل میں ہیں۔اس تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت تفسیری روایات پر تحقیقی کلام ہے۔
۲۔ الکلم الطیب(قرآنی ڈکشنری)۔ اس سے قبل میرٹھ کے مولاناقاضی زین العابدین مرحوم کے ساتھ ایک ’’قاموس القرآن‘‘ کوئی ۶۰ برس پہلے بھی ترتیب دیاتھا۔
۳۔ مفتاح القرآن (عربی) سورۃ فاتحہ طبع ہوئی، آل عمران تک غیر مطبوعہ ہے۔
۴۔ کلمات المثانی (مفردات القرآن)ناتمام
۵۔ قرآن کی حجتیں۔ (وفات کے وقت تک اس پرکام کررہے تھے)
۶۔ تحفۃ القاری بشرح صحیح البخاری عربی، مکمل (۱۹جلدیں)
۷۔ شرح مسند احمد بن حنبل اردو (۱۶جلدیں)
۸۔اقوم المسالک شرح مؤطا مالک (اردو ۶جلد، ناتمام)
۹۔ بخاری کا تحقیقی مطالعہ (بعض احادیث کی تحقیق وتنقید) ۳؍اجزا
۱۰۔ صحیح مسلم کا تحقیقی مطالعہ (۳؍اجزا) ناتمام
۱۱۔ تحقیق مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وواقعہ حرہ۔
۱۲۔ حدیث الافک العظیم (اردو میں تفسیر سورۂ نور کے نام سے طبع ہوئی) عربی غیر مطبوع ہے۔
۱۳۔ احادیث دجال کا تحقیقی مطالعہ (ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول مسیح کی تحقیق)
۱۴۔ حدوداللہ (تاوفات زیر تصنیف تھی)۔
شخصی احوال و اوصاف
نوخیزی ونوجوانی کی عمر بڑے جوش وولولہ کی اور مجاہدانہ تھی۔ صحت نہایت قابل رشک، گھڑسواری، شمشیر زنی اور بنوٹ کے ماہرتھے اور شکار کھیلا کرتے۔ ۱۹۴۷ء کے مسلم کش فسادات میں (بطور خاص جب گڑھ مکتیسور جل رہاتھا) انھوں نے اپنی قوت بازو، جرأت وشجاعت اور ہمت سے کئی مسلم لڑکیوں کو شرپسند ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ سے بچایا تھااور ان کے چنگل سے چھڑا کر لائے۔ اس کی پوری داستان اپنے ایک ناول غم میں رقم کی تھی (جو افسوس کہ ضائع ہوگیا)۔ اسی طرح انہوں نے عربی کے ایک تاریخی ناول واسلاماہ کا اردو ترجمہ بھی کیا تھا لیکن وہ بھی چھپ نہیں سکا۔
۱۷سال کی عمر میں ہی موضع ٹیالہ (غازی آباد) میں شادی ہوگئی اور چار برس بعد پہلی بچی عمارہ کی آمد ہوئیجو اب حجن آپا عمارہ کہلاتی ہیں۔دوسری بچی کی پیدائش میں اہلیہ کا انتقال ہوگیا تو میرٹھ کے موضع رائدھنہ میں ان کے ماموں چودھری توصیف احمد کی دختر نیک اختر نفیسہ بیگم (میری والدہ محترمہ)سے شادی ہوئی ۔ مولانا کے بقیہ لڑکے لڑکیاں انھیں کے بطن سے تولد ہوئی ہیں جن میں ہم پانچ بھائی اور چار بہنیں ہیں۔
علمی امتیازات و خصائص
علوم عربیہ واسلامےۃ میں تبحر کے ساتھ ہی علامہ اردو، فارسی وعربی کے ایک بڑے شاعر بھی تھے۔ انھوں نے جو مختصر دیوان چھوڑا ہے، اس میں اردو کے علامہ فارسی کی بھی بعض غزلیں ہیں۔ فن عروض کے امام تھے۔ اسی طرح نحو وصرف میں بھی بے نظیر مہارت پائی تھی۔ عام طور پر عربی مدارس میں ابتداکے کئی سال نحو صرف کی تعلیم میں ضائع کیے جاتے ہیں۔ علامہ کا طریقہ تعلیم انتہائی آسان، شگفتہ اور عملی تھا۔ محض ایک سال میں کتابوں کے بجائے کاپیوں پر قواعدو مثالیں لکھوا کر وہ صرف ونحو کی ضروری تعلیم دے دیا کرتے۔ اپنے بہت سے تلامذہ کو انھوں نے اسی طرح تعلیم دی۔ خود راقم نے ان سے ایک سال پڑھ کر عربی چہارم میں داخلہ لے لیاتھا۔
علامہ میرٹھی کی ایک بڑی علمی خصوصیت، جوانھیں معاصرین واقران سے ممتاز کرتی ہے، وہ علوم اسلامیہ اور بطور خاص قرآن وحدیث کا وسیع مطالعہ تھا اور وہ بھی اول درجے کے مصادر ومراجع سے۔ انھوں نے کبھی دوسرے او ر تیسرے درجہ کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ علوم قرآن سے متعلق ہمیشہ متقدمین کی نمایندہ اور بلند پایہ کتابیں اور تفسیریں ان کے زیر مطالعہ رہیں۔ ابن جریر طبریؒ ، ابن کثیرؒ ، بیضاویؒ ، رازؒ ی وزمخشریؒ اور ابو حیان الاندلسیؒ کا مطالعہ کرتے اور مؤخرالذکر کو زیادہ پسند کرتے۔ شاہان دہلی (شاہ عبد القادؒ ر وشاہ رفیع الدینؒ ) کے ترجمے انھیں پسند تھے۔ نیز اردو کے سبھی متداول تراجم وتفاسیر کو دیکھا تھا، لیکن سبھی کے بارے میں ناقدانہ رائے رکھتے تھے۔
حدیث کے باب میں، صحاح ستہ اور دیگر امہات کتب پر گہری نگاہ تھی، رجال کے دفتر از برتھے۔ مؤطا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، داری، مسند احمد وبیہقی فتح الباری و تہذیب التہذیب وغیرہ مسلسل مطالعہ میں رہیں۔ ساتھ ہی معاصرین کی چیزیں بھی دیکھتے رہتے۔ شرح مسند احمد بن حنبل کی تصنیف شروع کی تو مولانا عبداللہ رحمانی مبارک پوریؒ شارح مشکوٰۃ اور علامہ حبیب الرحمن اعظمیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے استفادہ کیا۔ بخاری پر انتہائی گہری نظر تھی۔ اس کی جلالت قدر کے بارے میں خود لکھتے ہیں: ’’کتاب اللہ قرآن کریم کے بعدصحیح بخاری کے علاوہ مجھے کسی کتاب میں دلکشی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ میرا چالیس سالہ مستقل احساس ہے۔‘‘ (میرامطالعہ، ص ۱۹۰، مرکزی مکتبہ اسلامی )
فقہ میں بھی یہی حال تھا۔ بطور خاص فقہ حنفی کے امہات کا گہرا استحضار تھا، اس لیے بدا ےۃ المجتہد سے خوش نہ تھے کہ صاحب بداےۃ نے حنفی نقطہ نظر پیش کرنے میں غلطیاں کی ہیں۔ اسی طرح متاخرین ومعاصرین علما کی چیزیں ان کے نزدیک غیر معیاری تھیں۔ علم فقہ پر زبردست گرفت اور مجتہدانہ نظر کے باوجود ان کی دلچسپی اصل میدان قرآن وحدیث اور ان سے متعلقہ علوم تھے جس کو اپنے ایک شعر میں یوں تعبیر کیا ہے:
جز کلام یار ہر تقریر بار گوش ہے
جز رخ جاناں کوئی منظر نہیں بھاتا مجھے
علمی زندگی کے تین دور
راقم کے خیال میں علامہ کی علمی زندگی کوتین ادوار میں بانٹا جاسکتا ہے۔ پہلے دور میں وہ فقہاے حنفیہ کے خوشہ چیں ہیں، لیکن نصوص کے راست مطالعہ و تحقیق اور تطبیق وترجیح کے بعد اگر دوسرے نتیجہ پر پہنچے ہیں تو پورے اعتماد اور جرأت کے ساتھ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور دوسرے مسالک کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی ’’اقوم المسالک الی مؤطا امام مالک‘‘ اس کی بین مثال ہے، البتہ حدیث کے مسلسل ومطالعہ وتحقیق نے انھیں تقلید جامدسے دور کردیا اور کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے سلفیت یا عدم تقلید کی طرف قدم بڑھائے۔ رفع الیدین، طلاق ثلاثہ اور عبادا ت کے زیادہ تر نزاعی مسائل میں اخیر تک ان کی رائے محدثین کے مسلک سے قریب تررہی ہے۔ انھوں نے خبر واحد کی ظنیت کے بارے میں فقہا کے نظریہ کا علمی تعاقب کیا۔ (ملاحظہ ہو رسالہ: تقریب المأ مول فی حدیث الرسول بر نہاےۃ التحقیق شرح مند ابو بکر صدیقی صفحہ ۱۹تا۷۵) اخیر تک ان یہی قطعی تحقیق تھی کہ خبر واحد اگر صحیح ثابت ہے تو قطعی الدلالت ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا دوسرا دور تھا۔ تیسرا دور وہ ہے جب انھوں نے علوم حدیث پر بے مثال تبحر حاصل کر لیا، علم الرجال کا وسیع مطالعہ کیا اور قرآن پاک کے مسلسل تحقیقی مطالعہ وتدبر نے فکر ونظر میں زبردست بصیرت پیدا کر دی تھی۔ اب انھوں نے روایت ودرایت کے لحاظ سے ذخیرۂ حدیث پر گہری نظر ڈالی، ایک ایک حدیث کو پرکھا، جانچا، مثالب کو تایا، مطاعن کو دیکھا حتی کہ خود اس فن پر ایک سند اور مرجع بن گئے۔
نقد حدیث
کتب حدیث میں حدیث کی سب سے اہم کتاب صحیح بخاری کو انھوں نے سب سے زیادہ پڑھا اور پڑھایا۔ قرآن کے بعد یہی کتاب انھیں سب سے زیادہ محبوب تھی، لیکن اس کے سلسلہ میں علما کا جو ایک غیر علمی اور خالص اندھی تقلید کا رویہ ہے کہ ’’ بخاری میں جو کچھ ہے، وہ سب صحیح ہے اور اِس پر تنقید نہیں کی جاسکتی‘‘ اس سے انھیں ذرا بھی اتفاق نہ تھا۔ بخاری و مسلم کی علمی عظمت وجلالت قدر کے پورے اعتراف کے باوجود ان کی سوچی سمجھی اور تحقیقی رائے یہ تھی کہ ان میں بھی متعدد کمزور اور غلط روایتیں جگہ پا گئی ہیں۔اس رائے کا انہوں نے نہایت جرات سے اظہار بھی کیا، چنانچہ اپنی ’’تحفۃ القاری‘‘ میں تفصیل سے ان روایات پر محدثانہ کلام کیاہے اور ان تحقیقات کا خلاصہ ’’بخاری کا مطالعہ‘‘ (۳؍اجزا) میں اردو زبان میں پیش کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں نام نہاد اجماع یا جمہور کے اتفاق کی انہوں نے کوئی پروا نہیں کی اور اسی وجہ سے بعض علمی طور پر کوتاہ قداور متعصب اہل حدیث علما، علامہ کو بھی منکرین حدیث کی صف میں لے جاکر کھڑاکرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ایسے ہی کم ظرفوں اور کم علموں کے لیے کہا گیا ہے کہ شعرمن بمدرسہ کے برد۔
زندگی کے تیسرے دور میں علامہ کا حاصل مطالعہ یہ تھا کہ اکثر اختلافی مسائل میں فقہاے امصار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت وامامت بدر جہا فائق ہے۔ ان کی رائے محدثین کے مسلک کے مقابلہ میں زیادہ لائق ترجیح ہے۔ اخیر کی تحریروں میں یہ رجحان صاف محسوس کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقہاے حنفیہ کی تقلید جامد کرنے لگے تھے، بلکہ متعدد مسائل میں ان سے اختلاف کیاہے۔
ذوق اجتہاد
کتاب وسنت کے مسلسل تحقیقی مطالعہ نے ان کے اندر اجتہادی بصیرت پیداکی۔ انھوں نے متعدد مسائل میں جمہور سے کھلا ہوا اختلاف کیا۔ قرأت سبعہ کا مسئلہ، اجماع کا ثبوت، نسخ کا مسئلہ، تحویل قبلہ، واقعہ افک، خبر واحد کی قطعیت کا مسئلہ اور اس کے علاوہ سیکڑوں احادیث اور آیات کی تشریح و توضیح میں وہ جمہورسے بالکل الگ رائے رکھتے ہیں اوران کا جرأت کے ساتھ اظہار بھی کیاہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ متاخرین میں ان کے تفردات سب سے زیادہ ہیں تو غالباً بے جانہ ہوگا نہ اس میں کوئی مبالغہ ہوگا۔ یہ تفردات یا اجتہادی رائیں دراصل ان کی دراکی، وسعت مطالعہ، تخلیقی ذہن، فکری شادابی، حاضر دماغی،علوم کے استحضار اور اعتماد ذاتی کی پیداوار ہیں۔
مسائل کے سلسلہ میں ان کی نظر جزئیات سے زیادہ کلیات پر رہتی تھی۔ فقہی نقطہ نظر میں وسعت تھی۔ ہر حال میں کسی ایک مسلک کی تقلید و تنقید کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے۔ علمی اختلاف و تحقیق ان کی نظر میں علما کی متوارث چیز تھی۔ چنانچہ انھوں نے محدثین کی رایوں اور فقہا کے اجتہاد ات سے خوب خوب اختلاف کیا ہے۔ فقہا حدود سے محدود معنی لیتے ہیں۔ علامہ نے اس کو پوری شریعت کے مترادف قراردیا ہے اور اسی تصورپر ان کی کتاب حدود اللہ مبنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاجرات کے سلسلہ میں ان کی رائے جمہور سے الگ ہے۔ مروان، یزید اور حجاج بن یوسف ثقفی کے بارے میں بھی ان کی تحقیق الگ تھی۔ وہ ان حضرات کے اقدامات کو کسی حد تک جواز کی حد میں داخل سمجھتے تھے۔شیعیت کو وہ اسلام کا سب سے بڑا داخلی انحراف سمجھتے تھے ۔ مولانا مودودیؒ کی کتاب خلافت وملوکیت سے مطمئن نہ تھے بلکہ ا س مسئلہ میں ان کا نقطۂ نظر ٹھیک وہی تھا جوامام ابن تیمیہؒ اور صاحب العواصم من القواصم قاضی ابن العربیؒ کا ہے۔ِ
شیدائے قرآن
علامہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، ضیاع وقت سے انھیں بڑی نفرت تھی۔ سفر میں ہوں، حضر میں، شہر میں ہوں یا گاؤں میں، بس ہر وقت مطالعہ غوروفکر، ہر وقت کچھ نہ کچھ تحریر۔ لائٹ موجود ہے تو بہتر، نہ آرہی ہو تو لالٹین کی روشنی کام آئے گی۔ سفر میں زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزارتے، مجلسوں اور جلسوں جلوسوں سے حتی کہ لوگوں کے زیادہ خلا ملا سے بھی وحشت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث اور قرآنیات پر اتنے بڑے بڑے کام انجام دے دیے جو بڑی بڑی اکیڈمیوں اور اداروں کے کرنے کے ہیں۔ ٹرین سے سفر کررہے ہیں یا بس سے کہیں جارہے ہیں تو بے تکی اور فضول باتوں کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کررہے ہیں۔ ان کی تلاوت قرآن نری تلاوت نہیں، تدبر کی تلاوت ہوتی تھی۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مستقل پڑھتے رہتے تھے۔ تلاوت کے دوران اکثر آنکھوں سے آنسو ٹپکتے۔ یہی نمازمیں قراء ت کے وقت ہوتاتھا۔قرآن ان کے لیے اصل مصدر و مرجع تھا۔ تمام علوم اسلامیہ میں وہ قرآن ہی کوحکم بناتے اور اسی کی طرف رجوع کرتے تھے۔
نمازوں کے بعد دیر تک مسنون اور اذکار کا اہتمام ہمیشہ رہا۔ جہاں رہتے اور جس کمرے میں بیٹھتے، وہ صبح سے شام تک قال اللہ وقال الرسول کے ترانوں اور تلاوت قرآن کے زمزموں سے گونجاکرتی۔ ان کی نوجوانی کے ایام میں ذرائع مواصلات محدود تھے۔ اس وقت گھوڑے سے یا پیدل سفر کرتے اور دوران سفر بڑی سے بڑی مسافت تلاوت قرآن میں طے کرلیتے۔ ہر رمضان المبارک میں کئی کئی قرآن ختم کرتے۔ طریقہ یہ ہوتا کہ عشا کے بعد تراویح میں الگ قرآن پڑھتے، تہجد میں الگ۔ دن کو حافظ عبدالخالق صاحب (رادھنہ گاوں کی جامع مسجد کے امام اور ہمارے حفظ قرآن کے استاد) کو مستقل کئی کئی پارے سنایا کرتے۔ زندگی کے آخری ایام تک حافظہ قابل رشک رہا۔ قرآن انتہائی پختہ یادرہا اور اسی شان سے اس کی تلاوت جاری رہی حتی کہ وفات کے وقت بھی قرآن کی تلاوت دیر تک کرتے رہے تھے۔
شخصیت پرستی سے اجتناب
راقم نے اپنے شعور کے بعدتقریباً ۲۰ سالوں سے انھیں مسلسل دیکھا اور برتاہے۔ مسلمانوں میں شخصیت پرستی ایک مرض کی طرح پھیل گئی ہے۔ مختلف مکاتب فکر، فقہی مسالک، جماعتیں اور تنظیمیں وغیرہ مختلف شخصیتوں کی اسیر ہیں اور انھی کی عینک سے دین کو دیکھتی اور سمجھتی اور سمجھاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو سبھی نے پس پشت ڈال رکھا ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال (یہ دیکھو کہ کیا کہا، یہ نہ دیکھو کہ کس نہ کہا) لیکن والد صاحب رحمہ اللہ علیہ کے متعلق یہ عاجز پورے وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ شخصیت پرستی کے مرضی سے اللہ نے انھیں پورے طور پر محفوظ رکھا تھا۔ ماضی کی طرح اس صدی میں بڑی بڑی شخصیات ہوئی ہیں، لیکن والد صاحب علوم میں رسوخ کے اس درجہ پر تھے کہ ماضی وحال کی کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے انھیں مرعوب نہیں دیکھا۔
اپنے اساتذہ کا ذکر احترام سے کرتے، لیکن دواستادوں مولانا اختر شاہ خانؒ امروہوی اور مولانا حسین احمد مدنیؒ کا تذکرہ بڑے ہی احترام کے ساتھ کرتے۔ انھی دونوں سے زیادہ متأثر بھی رہے۔ ماضی قریب کے علما میں مولاناحمیدالدین فراہیؒ سے بہت مسائل میں اختلاف کے باوجود ان کا ذکر بلند کلمات میں کرتے کہ بر صغیر میں قرآن پر براہ راست غور وفکر اور اکتساب کی مبارک فضا کا آغاز انھی سے ہوا اس چیز کو بہت بڑا کارنامہ قرار دیتے تھے۔ قدیم مفسرین میں ابو حیان اندلسیؒ کو زیادہ پسند کرتے اور طالبان قرآن کو اس کے مطالعہ کا مشورہ دیتے۔ قرآن سے امت کی دوری کا بڑا سبب اسرائیلیات کے رواج، تصوف کی خرافات کے ساتھ واعظوں کی داستان گوئی اور راویان حدیث کی روایت بازی کو قرار دیتے تھے۔ ماضی کے علما وائمہ میں سب سے زیادہ قائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے تھے بلکہ یہ تک فرماتے کہ امامت کے حقیقی مصداق صرف ابو حنیفہؒ ہیں۔ تاہم متاخرین حنفیہ پر خوب تنقیدیں بھی کی ہیں۔
شان قلندری
علامہ ایک مفلوک الحال گھرانہ میں پلے بڑھے، لیکن ابتدا ہی سے غیرت ، توکل ، خودداری اور قلندری کی شان تھی جس میں زندگی بھر فرق نہیں آنے دیا۔ جب نئے نئے پڑھ کر وطن واپس آئے تو بعض رشتہ داروں اور احباب کے کہنے پر للیانہ گاؤں میں ایک مدرسہ ازہر العلوم کھولا۔ کچھ عرصہ بعد ایک مسودہ (بیان اللسان) میرٹھ کے قاضی زین العابدینؒ کو فروخت کرکے ۱۹۵۰ء میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ کلمہ حق کہنے اور غلط کوغلط بتانے میں انتہائی بے باکی اور جرأت کی دولت سے مالا مال تھے۔ اسی دوران علماء دیوبند کا ایک حلقہ اور ان کے مسترشدین مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر ناروا قسم کی تنقیدیں کرنے اور گمراہ پروپیگنڈے میں مشغول تھے، لیکن مولانا نے نہ صرف یہ کہ اپنے استاد وں اور مشائخ سے اس معاملہ میں کھل کر اختلاف کیابلکہ بہت سی چیزوں میں پوری جرأت وقوت کے ساتھ جماعت اور مولانا مودودیؒ کی حمایت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علاقہ کے بعض فتنہ بازمولویوں اور پیروں نے عوام کو ان کے خلاف بھڑکادیا اور انھیں’’مودودیا‘‘ مشہور کردیا۔ لوگوں نے مدرسہ کا تعاون چھوڑدیا۔ حج سے واپس آنے کے بعد اس صورت حال کا سامنا ہواتو مدرسہ کو خیر باد کہہ کر پھر سے درس وتدریس اختیار کرلی۔ حیدرآباد گئے، وہاں کریم نگر میں جماعت اسلامی کی نگرانی میں دارالہدیٰ کھولا گیا جس کے پہلے استادآپ ہی تھے۔ وہیں جماعت سے باقاعدہ وابستگی ہوئی اور رکن بنے، لیکن خالص علمی افتاد طبع ہونے اور فکری اختلاف کی بنا پر جلدہی اس تحریک کے جھمیلوں سے نکل آئے۔ اس کے بعد مولانا مجیب اللہ ندوی ؒ صاحب کے ساتھ مل کر جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کی بنا وتکوین میں بھی حصہ لیا۔
زندگی بھر مدارس اسلامیہ میں قلیل تنخواہ پر علوم اسلامیہ کی خدمت کی۔ کبھی سرمایہ داروں اور ثروت مندوں کا رخ نہیں کیا۔ کبھی جماعتوں، تنظیموں اور ملی اداروں کے ارباب حل وعقد کی جبہ سائی اور کفش برد اری کا تصور بھی حاشیہ خیال میں نہیں آیا۔ کتابیں لکھتے رہے، الماریوں میں مسوادات کی شکل میں جمع ہوتی رہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی کی جھوٹی خوشامد یا جھوٹی تنقید کرکے اپنی تحریر چھپوانے کا سامان کریں، چنانچہ مولانا اسعد مدنیؒ صدر جمعیت علماء ہند (جو شیخ زادہ بھی ہیں) کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ تفسیر میں مودودی ؒ صاحب پر تنقید کی جائے تو طباعت کے مصارف ہم اٹھائیں گے۔ جماعت اسلامی حلقہ آندھرا پردیش کا وفد یہ تجویز لے کر آیا کہ اپنی تفسیر سے مولانا مودودیؒ پر تنقیدیں نکال دیں تو وہ اس کی اشاعت میں تعاون کریں گے، اس وفد کو بھی لوٹا دیا، مگر عدل وانصاف، امانت ودیانت اور علمی وقاروغیر ت پر آنچ نہ آنے دی۔ مدارس کے ارباب اہتمام سے بھی اکثر تصادم ہوجاتا۔ وہ چاہتے کہ آپ ٹھیک تقلیدی مزاج کے ساتھ ہی کام کریں، لیکن علامہ شان قلندری وبے نیازی کے ساتھ بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے، نہ مرعوب ہوتے نہ اپنی کسی رائے سے دست بردار ہوتے۔ معاصرین میں یہ شان بے نیازی ان کا امتیاز تھی۔
تزکیہ و احسان
علامہ میرٹھیؒ کے اساتذہ وشیوخ میں بیعت واردات کی مستحکم روایت ہے، لیکن تحقیقی ذہن، شخصیت پرستی سے نفور اور قرآن سے شغف، یہ ان کی شخصیت کے عناصر ترکیبی تھے، اس لیے جہاں تک راقم کو معلوم ہے، وہ کسی حلقہ ارادت سے وابستہ سکہ بند صوفی نہ تھے۔ البتہ ان کے جن احوال ومقامات کا مشاہدہ ۲۰ سالوں سے ہوتا رہا ہے، ان کو سامنے رکھ کر بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ ذات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق، تقویٰ وپرہیز گاری، انابت اور رجوع الی اللہ کی جو کیفیت ان کو حاصل تھی، وہ موجودہ دور کے مروجہ حلقائے طریقت ومشیخت کے لوگوں کو شایدنصیب ہوتی ہو۔
تزکیہ وسلوک ’’ہو ہو‘‘ کرنے یا الااللہ کی بے روح ضربیں لگانے، بزرگوں کے عرس اور ان کے مزاروں پر چلہ کشی کا نام نہیں، وہ تو دراصل عرفان ذات، جذبہ وشوق اور خدا کے لیے جذبات محبت سے عبارت ہے۔ اس کے لیے جذبہ شکر اور والہانہ عقیدت سے ہی سلوک کا جوہر تیار ہوتاہے۔ محبت کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو بندہ کو اپنے خالق ومالک اور پالن ہار سے ہوتی ہے اور اس محبت کے بغیر تو ایمان بھی معتبر نہیں۔ کسی شخص کے ظاہری احوال اور کاموں کو دیکھ کر اگر اس کے باطن کے بارے میں رائے قائم کرنا درست ہو تو مبالغہ کہا جاسکتاہے کہ حب مال، حب جاہ اور تنگ دلی سے ان کے قلب کو صاف کردیاگیا تھا اور وہ ان شاء اللہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحوں (جو لوگ نفس کی تنگی سے بچا دیے گئے، وہی کامیاب ہیں۔تغابن:۱۶) کے خاص مصداقوں میں سے ہوں گے۔ ان کے چہرہ سے پاکیزگی جھلکتی اور پیشانی سے نور کی بارش ہوتی تھی۔
حادثہ وفات
ڈیڑھ سال قبل نماز کو جاتے ہوئے راستہ میں گرگئے تھے۔ دوچار دن تو کچھ معلوم نہ ہوا، پھر دائیں ٹانگ میں درد محسوس ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ جانچ کرانے پر معلوم ہوا کہ معمولی سا فریکچر ہے۔ علاج ہوا لیکن فائدہ نہ ہوا تو ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا۔ آپریشن ہوا۔ اس کے بعد توقع تھی کہ ٹانگ ٹھیک ہوجائے گی، لیکن آپریشن سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور ’’مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی‘‘ والامعاملہ ہوگیا ۔ اس بیماری میں تقریباً چودہ مہینے بستر پر رہے۔ حوائج ضروریہ بھی بستر پر کرائے جارہے تھے۔ اس کے باوجودلکھنے پڑھنے کا کام جاری تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت وتدبر کے معمول میں کوئی کمی نہیں آئی۔
۴؍جنوری ۲۰۰۵ء کو یکایک ایک حادثہ پیش آیا کہ آپ کے دوسر ے صاحبزادے (میرے برادر مکرم) جناب مولانا انظارالحقؒ صاحب (بانی مدرسہ ازہر العلوم رادھنہ) اچانک علی الصباح حرکت قلب بند ہوجانے سے وفات پاگئے۔ انہوں نے عمر عزیز کی صرف ۴۲ بہاریں دیکھیں۔ یہ تمام اولاد میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ شروع سے آخر تک تعلیم بھی آپ نے ہی دی تھی۔ اس حادثہ فاجعہ نے زیادہ صدمہ پہنچایا۔ عید کے دوسرے دن طبیعت ناساز ہوئی تھی۔ قرآن پڑھواکر سنا، افاقہ ہوگیا۔ تیسرے دن بھی طبیعت خراب ہوگئی۔ پھر سورہ ےٰسین پڑھوا کر سنی، طبیعت بحال ہوگئی۔ ۲۴؍جنوی کو اچھی دھو پ نکلی تھی۔ سارے دن دھوپ میں بیٹھے ہشاش بشاش تھے۔ ’’قرآن کی حجتیں‘‘ پڑھوا کر سنی۔ پھر لکھنے میں مشغول ہوگئے۔ دوپہر میں مجھے طلب کرکے اپنے مسودات دکھائے۔ اپنا ذخیرۂ کتب، صحاح اور ان کی شرحیں، تفسیر مفتاح القرآن اور تحفۃ القاری شرح صحیح بخاری کے مسودے خود اٹھ کر اور الماریوں کے پاس جا جا کر دیکھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ان کی آخری زیارت ہے۔ یہ کتابیں ہی کل زندگی کا سرمایہ تھیں۔ مغرب کے بعد لوگ ملاقات کے لیے آتے رہے، عشا کی نماز پڑھ کر روز مرہ کے اور ادووظائف پڑھے۔ پھر کچھ دیر کے لیے سوگئے اور اچھی نیند سوئے۔ تقریباً ساڑھے بارہ بجے آنکھ کھلی تو وضوکرکے تلاوت قرآن شروع کی اور ایک گھنٹہ تک کرتے رہے۔ پھر بڑے بھائی سے مدرسہ ازہرالعلوم کے بارے میں باتیں کیں ۔ دو بجے سے بعد تکلیف شروع ہوئی۔ دوا وغیرہ لی۔ مقامی ڈاکٹر کو بلایاگیا۔ اس نے انجیکشن لگائے۔ اس کے بس دو تین منٹ بعد ہی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پورے قصبہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ آفتاب علم غروب ہوا، وقت کا امام الحدیث چلا گیا۔
جا چکی خاموش ہو کر شمع ہوئے آسماں
عالم بالا میں پایا ہے سراغ آرزو
(ازہرؔ )
متعدد علمی مجلات اور تحقیقی رسالوں نے آپ کی وفات پر تعزیتی نوٹ اور شذرے شائع کیے جن میں البعث الاسلامی ندوۃالعلماء لکھنؤ، الرشاداعظم گڑھ، ماہنامہ ترجمان جدید دارالعلوم (دہلی) اور اردوبک ریویو خاص ہیں۔
میری علمی و مطالعاتی زندگی (پروفیسر عبد القدیر سلیم سے انٹرویو)
عرفان احمد
انٹرویو: عرفان احمد/ عبدالرؤف
اﷲ کے فضل وکرم سے میری پیدائش ایک دین دار،علمی گھرانے میں ہوئی۔والد محمد سلیم عبداﷲؒ روایتی دین دار یا مولوی نہیں تھے۔ ان کاتعلق غازی پورسے تھا اوروہ میرے دادامرحوم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرکے غیر منقسم ہندوستان کے صوبے سی پی (Central province) کے شہرامراؤتی میں بس گئے تھے۔ یہاں اکثریت ہندؤوں کی تھی، مسلمانوں کی آبادی ۴فی صد کے لگ بھگ تھی۔ہندوستان کی زبان مراٹھی تھی،لیکن مسلمان جنوبی ہند/حیدرآباد دکن جیسی اُردو بولتے تھے۔تاہم ہمارے گھرانے پریوپی کی اُردو ہی کے اثرات رہے اور ہماری مقامی اُردو سے کچھ مختلف رہی۔ میرے ننھیال کے بزرگ قاضی تھے اوردہلی سے یہاں آکربس گئے تھے۔
میرے والد رحمتہ اﷲ علیہ نے ابتدائی تعلیم امراؤتی ہی میں حاصل کی،پھرانہوں نے مولوی محمدشفیع مرحوم(اورینٹل کالج لاہور) سے خط وکتابت کی اوراُنہیں اس کالج میں داخلہ مل گیا۔ مولوی محمدشفیع صاحب نے کہا کہ سی پی سے آکر یہاں داخلہ لینے والے آپ پہلے طالب علم ہیں۔ وہاں اُنہیں ہاسٹل میں بھی داخلہ دیادیاگیا۔وہاں سے والدصاحب نے فارسی میں فاضل کی سندلی۔ امراؤتی میں انہیں نارمل سکول (ٹیچرز ٹریننگ سکول)میں مُعلم ادبیات کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ انہوں نے اُردو کی درسی کتابیں (’’نئی کتاب‘‘) لکھیں جونول کشور پریس لکھنو سے شائع ہوئیں۔ان کے علاوہ ’’اُردو کیسے پڑھائیں؟‘‘ اور مختلف موضوعات پرمنتخب قرآنی آیات کامجموعہ البینات شائع کیا۔ وہ اپنے ادارے کے تعلیمی مُجلے ’’بہارستان‘‘ کے مدیربھی تھے۔ یہاں انہوں نے ’’ادارہ قرآنیہ‘‘بھی قائم کیاتھا جوقرآنی احکام وآیات سے متعلق ذکریٰ کے عنوان سے چھوٹے چھوٹے رسائل بھی شائع کرتاتھا۔اس ادارے کاایک کتب خانہ بھی تھا۔
مطالعہ کاشوق مجھے والدین سے ورثہ میں ملا تھا۔ والدصاحب جن جرائد کودیکھتے تھے، اُن میں جامعہ (دہلی)، معارف (اعظم گڑھ)، ترجمان القرآن (حیدرآباددکن /لاہور)، ہمایوں (لاہور)، اورینٹل کالج میگزین (لاہور)، نگار (لکھنو) اور صدق/صدق جدید شامل تھے۔ والدہ صاحبہ اوربڑی بہن کے لیے’’عصمت‘‘، ’’تہذیب نسواں‘‘ آتے تھے۔ راشد الخیری، مولوی ڈپٹی نذیر احمد اور خواجہ حسن نظامی کی تحریروں سے میرا تعارف لڑکپن ہی میں ہوگیا تھا۔ اپنی خالہ جان سے ’’عذرا‘‘(She) اور’’عذراکی واپسی‘‘ کی داستانیں کئی دن قسطوں میں سنیں۔ نہ صرف گھرکا ماحول مطالعے میں ممدومعاون تھا،بلکہ جن مدارس میں، میں نے تعلیم پائی،وہاں بھی اچھے کتب خانے دیکھے۔نارمل سکول کی لائبریری سے منسلک میرے والد مرحوم کاکمرہ تھا۔وہاں کتابیں دیکھنے کھولنے اوراُلٹ پلٹ کرنے پرکوئی پابندی نہ تھی۔ گھرمیں بھی والد مرحوم کی اچھی خاصی نجی لائبیریری تھی۔تقسیم کے بعدہم اس ذخیرے کاایک مختصر ساحصہ ہی ساتھ لا سکے۔ باقی کتابیں جہاں رکھوائی گئی تھیں کہ حالات بہترہوں گے تومنگوالیں گے۔ فسادیوں کی لُوٹ مارمیں ضائع ہو گئیں۔
مطالعہ کاشوق چوں کہ بچپن سے تھا،اس لیے کسی خاص موضوع کوہدف بناکرنہیں پڑھا۔ جو کتاب سامنے آئی، اُلٹ پُلٹ کردیکھی اورجہاں تک دلچسپی ہوئی، مزہ آیا، پڑھنے لگے ورنہ رکھ دی۔’’تذکرہ غوثیہ‘‘سے لے کر’’الف لیلہ‘‘ تک لڑکپن ہی میں پڑھ ڈالیں(والدہ صاحبہ نے میرے ہاتھ میں ’’الف لیلہ ولیلہ‘‘دیکھی توکہا، کہاں سے یہ واہیات کتاب لے آئے ہو؟ابامرحوم نے کہا، پڑھنے دو۔
مطالعہ کے ضمن میں میراکوئی مخصوص موضوع نہ تھا۔تاریخ وسوانح سے لے کر دینیات ،سیاسیات،ادب(تنقید) شاعری،ناول،افسانے،غرض ہرطرح کارطب ویابس پڑھنے کی کوشش کی کچھ سمجھ میں آتا تھا اورکچھ نہیں۔شایدیہی وجہ ہے کہ پہلے ایم۔اے کے لیے میں نے ایک بہت ہی معمولی مضمون کے لیے’’تخصیص‘‘کی، فلسفہ جومابعد الطبعیات کے علاوہ اورکون سے علوم ہیں،جنہیں پھلانگنے کی کوشش نہیں کرتا؟
(Philosopher are the spectators of all time and all existence)
ایک طویل علالت کی وجہ ’’اُردو ہائی سکول‘‘امراؤتی میں آٹھویں جماعت ہی سے میرا رسمی تعلیمی سلسلہ منقطع ہوگیا تھا، لیکن پڑھائی کاسلسلہ نہ رُکا۔قرآن مجید توگھرپرمولوی صاحب آکرپڑھاجاتے تھے ،والدصاحب نے قرآن مجیدکاترجمہ پڑھایا۔اُ ن کاخیال تھاکہ اُردو جاننے والوں کے لیے قرآنی عربی کوسمجھ لینا زیادہ مشکل نہیں۔ عربی زبان کے بہت سے الفاظ جوقرآن مجید میں ہیں، اُسی مفہوم یاملتے جلتے مفہوم میں اُردو میں بھی مستعمل ہیں (حمد، اﷲ، رب، عالم/عالمین ایسے سینکڑوں الفاظ)۔ تھوڑے ہی الفاظ ایسے ہیں جن سے اُردو داں قطعاً ناآشنا ہوں گے۔ عربی کے تھوڑے سے قواعد زبان سے آشناکرکے کسی طالب قرآن کوآسانی سے مضامین ومفاہیم قرآن تک لے جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ بہت سے شائقین کوقرآن کریم کی تعلیم دی اور اسی اُصول پر ’’مصباح القرآن‘‘ مرتب کی جوزیرطبع ہے۔ یہ نہ صرف ایک منفرد قرآنی لُغت ہے،بلکہ قرآنی/عربی گرامرکی ایک ایسی کتاب ہے جس سے استفادہ کرکے اُردو دان قرآن کے مطالب تک خودآسانی سے پہنچ سکتے ہیں، یعنی قرآن کاخود ترجمہ سمجھ اور کرسکتے ہیں۔
تقسیم ملک کے کچھ عرصے بعدہمیں’’آزاد‘‘ہندوستان سے ہجرت کرکے پاکستان آناپڑا۔والد صاحب نے وقت سے پہلے ہی پنشن لے لی تھی۔یہاں ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں منتقل ہوگئے۔والد صاحب نے کراچی کے’’دہلی پنجاب نیشنل ہائی سکول‘‘ میں میٹرک میں داخل کرادیا۔یہ ایک نجی تعلیمی ادارہ تھا۔مالکان جوپڑھے لکھے اور ہمدرد استاد بھی تھے، دہلی سے تعلق رکھتے تھے اورپنجاب میں میٹرک کے طلبہ کوتیارکرتے تھے۔طلبہ پر اساتذہ کی شفقت ومحنت مثالی تھی۔ سکول میں طلبہ کی نشست فرشی تھی۔دریاں صاف ستھری ہوتی تھیں۔اُوپرٹین کی چھت تھی۔سکول میرے گھرسے کوئی ۵میل دُور ہوگا۔پیدل جاتے تھے اورراستے میں جیومیٹری کی تھیوریز دُہراتے اوردوسرے سبق یادکرتے جاتے تھے۔ آج دیکھتا ہوں کہ بچے ایک آدھ کلومیٹرکے لیے بھی بس کے بغیرسفرنہیں کرتے۔
جتنی محنت اوریکسوئی سے پڑھائی کی، شایدپھرنصیب نہ ہوئی۔ لاہورجاکرامتحان دیا۔سکول مالکان ساتھ گئے، انہوں نے طلبہ کے ٹھہرنے کے لیے ایک سکول میں انتظام کیاتھا۔ رات کووہ’’کوچنگ‘‘کرتے اورصبح کوہم طلبہ امتحان دینے جاتے۔ میٹرک میں میری فرسٹ ڈویژن آئی۔اس میں بڑا دخل مشفق اساتذہ اورسکول کے منتظمین کاتھا۔آج چاروں طرف نظرڈالتا ہوں توایسے نجی تعلیمی ادارے نظرنہیں آتے۔سرکاری سکول بدنام ہوگئے ہیں کہ ان میں پڑھائی نہیں ہوتی، اساتذہ دلچسپی نہیں لیتے۔اُنہیں اپنی کوچنگ/ٹیوشن میں زیادہ دلچسپی ہے یااپنا کوئی دوسرا کاروبار ہے جو ان کے اوقات اورمحنت کا بہتر مصرف ہے۔ ہرطرف پرائیویٹ سکولوں اورکوچنگ سینٹروں کی بھرمارہے۔اچھے اور معیاری سکول غریب توکیامتوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دورہیں۔
میٹرک کے بعدسندھ مسلم کالج کراچی میں داخلہ لیا۔ معاشیات،شہریت اورعربی میرے مضمون تھے۔یہاں بھی اساتذہ اچھے اورمحنتی تھے۔ میٹرک اورانٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی جامعہ کراچی لیا کرتی تھی،ابھی ان کے لیے بورڈ وجودمیں نہیں آئے تھے۔ انٹرمیں بھی میں نے فرسٹ ڈویژن میں کیا اورپہلی پوزیشن لی۔اس زمانے کاایک واقعہ میرے دل پرنقش ہے۔ ہماری مالی حالت بہت اچھی نہ تھی۔ سال کی ۱۴۴؍ روپے فیس بھی ایک بڑی رقم محسوس ہوتی تھی۔ کالج میں داخلے کے کچھ دن بعدنوٹس بورڈ پراطلاع دیکھی کہ فیس کی معافی یانصف فیس کے لیے درخواست کے فارم دفترسے لیے جاسکتے ہیں۔میں نے ایسافارم لیا، اسے پرکیا۔ایک جگہ والد کے دستخط ہونے تھے۔ابامرحوم کے پاس لے گیا۔ پوچھا، کاہے کافارم ہے؟میں نے کہا، فیس کی معافی کے لیے درخواست ہے۔فرمایا، ہم نے تمہیں کالج میں داخل کرایا تواخراجات کااندازہ کر لیا تھا۔ ہم فیس معاف نہیں کروائیں گے۔ یہ رقم کسی حقیقی مستحق کے کام آئے گی۔
بی۔اے میں میرے اختیاری مضامین معاشیات اور فلسفہ تھے۔فلسفہ میں ایک پرچہ’’نفسیات‘‘کابھی ہوتا تھا جسے پروفیسر فضل الرحمن پڑھاتے تھے۔ وہ عرصے تک انگلستان میں رہے تھے اورسنہرے بالوں اورنیلی آنکھوں سے یورپین معلوم ہوتے تھے۔ سائیکل پرکالج آتے۔اس زمانے میں اساتذہ بسوں اورسائیکلوں ہی پرکالج آتے تھے۔دوسراپرچہ ’’اخلاقیات‘‘ پروفیسر جمیلہ خاتون پڑھاتی تھیں۔بعدمیں انہوں نے اقبال پرتحقیقی مقالہ لکھا اورپی ۔ایچ ۔ڈی کی سندلی۔ اسلامیات جولازمی مضمون تھا، مولانا یحییٰ ندوی جیسے قابل استادپڑھاتے تھے۔ یہیں میری ملاقات اوردوستی ظفراسحق انصاری، منظور احمد، خورشید احمد، خرم جاہ مراد، محمد مسلم سجاد، سیدمحمد یاسین اوربہت سے دوستوں سے ہوئی۔ ظفراسحق کے والدصاحب،مولاناظفراحمدانصاری کے ہاں اکثرآناجانارہتا تھا۔وہیں ماہرالقادری مرحوم اوربہت سے دوسرے لوگوں سے تعارف ہوا۔سندھ مسلم کالج ہمارے گھرسے کوئی ڈھائی میل دورتھا۔پیدل ہی آناجانا رہتا تھا۔
جامعہ کراچی میں ایم۔اے شعبہ فلسفہ میں داخلہ لیا۔ ڈاکٹر محمد محمود احمد (ایم۔ایم۔احمد) صدر شعبہ تھے۔ اساتذہ میں طیب حسین انصاری اورانیس احمدصاحب کے علاوہ مولانا فضل الرحمن (اسلامک مشن) اورفادر ریمنڈ (سینٹ پیڑکس، نفسیات) سے پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔جامعہ کراچی کی اپنی کوئی عمارت نہیں تھی۔پرنس اسٹریٹ (ڈاؤ میڈیکل کالج/سول ہسپتال) کے قریب رنچھوڑ لین کی کچھ متروکہ عمارتوں میں جامعہ کے مختلف شعبے اور دفاتر تھے۔ وائس چانسلر اے۔بی۔اے۔حلیم (اباحلیم) بھی یہیں بیٹھتے تھے۔ اساتذہ اورانتظامیہ کے افراد میں بڑی سادگی تھی۔ ہمارے صدر شعبہ تانگے/گھوڑاگاڑی میں کینٹ اسٹیشن کے قریب اپنی رہائش گاہ سے جامعہ آتے اوراسی طرح واپسی ہوتی۔ اکثرشیروانی اور ترکی/رومی ٹوپی میں ہوتے۔ کبھی کبھی سوٹ یاآکسفورڈ کا بلیزر بھی پہن کرآتے۔وہ وائس چانسلر پروفیسراے بی حلیم کے بھانجے تھے اوردونوں ایک ہی متروکہ (دو منزلہ) عمارت میں رہائش پذیرتھے۔لیکچرر بننے کے بعد بھی اکثرڈاکٹرصاحب کے گھر جانا ہوتا تھا۔ گاندھی گارڈن کے قریب جہاں ہمارا فلیٹ تھا، وہاں سے پیدل ہی آمدورفت ہوتی تھی۔ ناظم آبادمنتقل ہوگئے توصدرتک بس میں اوروہاں سے پیدل اپنے استاد کے گھرجاتے تھے۔
ایم۔اے کرنے کے فوراً بعدہی مجھے عثمانیہ کالج میں فلسفہ پڑھانے کے لیے ملازمت مل گئی۔ ایک دن والدہ صاحبہ نے اخبارمیں اشتہاردیکھا توکہا، سرکاری کالج میں لیکچرر شپ کے لیے درخواست کیوں نہیں دے دیتے؟میں سندھ کی نظامت تعلیم (سعید منزل، بندروڈ) گیا۔ ڈائریکٹر نظامانی صاحب سے ملا،اﷲ انہیں جنت نصیب کریں۔بڑی محبت سے ملے اورجلدہی مجھے تقرری کا خط مل گیا۔اس زمانے میں ’’رسمیات‘‘ نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس طرح گورنمنٹ کالج نواب شاہ میں میری پہلی (سرکاری) تقرری ہوئی۔ اس کے بعدسندھ کے کئی کالجوں میں تدریس کے لیے جانا ہوا۔ میرامشاہدہ تھا کہ سندھ کے سرکاری کالجوں کے کتب خانے بڑے معیاری ہوتے تھے۔ نہ صرف کتابیں بلکہ ملکی اور غیرملکی جرائدکی خریداری عام بات تھی۔ کتب خانوں کے لیے بڑی رقوم رکھی جاتی تھیں اورانگریزی اوراُردوکتابوں کی خریداری کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ بدقسمتی سے یہ بات اب ماضی کی داستان ہے۔
اﷲ کافضل وکرم ہی ہے کہ میرابچپن لڑکپن اورموجودہ عمرکوکتابوں کا ماحول میں میسر ہوا۔لڑکپن میں عرب شاعرمتنبی کا ایک شعر پڑھا تھا کہ دنیا میں نشست کے لیے برق رفتار گھوڑے کی پیٹھ سے بہترکوئی جگہ نہیں اورزمانے میں بہترین دوست کتاب ہے۔ مختلف ادوار میں میری پسندیدہ کتابوں میں الف لیلہ، قصرصحرا (عظیم بیگ)، صنوبرکے سائے، میری ناتمام محبت (حجاب امتیازعلی)، فسانہ آزاد (رتن ناتھ سرشار)، واردات، دودھ کی قیمت (منشی پریم چند)، میرے بھی صنم خانے، آگ کادریا (قرۃ العین حیدر)، Portait of a lady (ہنری جیمز)، آرتھرکائن ڈائل (شرلاک ہومز والے) کی ساری کتابیں، جیمرمچنر کی اور ابن صفی کی ساری کتابیں،ایم اسلم اورسیم حجازی کے ناول، پطرس بخاری، قدرت اﷲ شہاب، مختار مسعود، ممتاز مفتی، اشفاق احمد کی کہانیاں نوجوانی میں پڑھیں۔ انگریزی میں رسائل میں Reader's Digest اور پھر بعد میں New weekمیرے پسندیدہ رسائل تھے۔ بعد میں Economist سے تعارف ہواورمیرا خیال ہے کہ ہفت روزوں میں یہ بہت اچھا رسالہ ہے۔
میرا زیادہ ترمطالعہ اُردواورانگریزی زبانوں میں ہے۔ابتدامیں کچھ کلاسیکی عربی ادب سے شناسائی ضرورتھی۔اس کے علاوہ فارسی کی بھی کچھ ابتدائی کتابوں کا مطالعہ کیاتھا۔میراخیال ہے کہ اچھی اُردوکے لیے عربی اورفارسی سے آشنائی بھی ضروری ہے۔بدقسمتی سے آج تعلیم کی شاہراہ(mainstream)ہیں۔ میں ان دونوں زبانوں سے بے اعتنائی برتی جارہی ہے،لیکن وہ معیاری/علمی اُردو سے نابلدہوگئے ہیں،اور نہ صرف یہ کہ وہ پچھلی(بیسویں)صدی کے اُردوعلمی ورثے سے محروم ہوتے جارہے ہیں۔بلکہ سنجیدہ علمی افکارکواپنی’’قومی‘‘سرکاری زبان میں اظہارکے قابل بھی ہیں رہے۔
سنجیدہ ادب میں جن مصنفین اورتحریروں نے مجھے متاثرکیا،ان میں شیخ احمدسرہندی(مکتوبات اوردوسرے رسائل) شاہ ولی اﷲ کی بعض تحریریں، مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی،مولانا ابوالکلام آزاد،مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا جعفرپھلواری، مولوی محمدعلی لاہوری(خصوصاً سیرۃ پر اُن کی تصنیف)۔ اُن کی تفسیرکے بعض افکارسے مجھے اختلاف ہے جہاں وہ سیداورجدیدیت سے متاثر محسوس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرحمیداﷲ(خصوصاً عہدنبوی میں نظام حکمرانی اور خطبات بہاولپور)، شبلی اورسیدسلیمان ندوی کی سیرت النبی۔تفاسیرمیں مولانا سیدابواعلیٰ مودودی کاایک منفردمقام ہے۔ ان کی تفہیم القرآن بلاشبہ تفسیری ادب میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔تاہم ایک طویل دورانیے میں تکمیل پذیر ہونے کی وجہ سے بعض مقامات پروہ اپنی ابتدائی انقلابی فکرسے ہٹے ہوئے نظرآتے ہیں۔
مطالعہ فلسفہ کے ابتدائی دورمیں، میں اقبال کے خطبات سے بھی متاثرتھا، لیکن بعدمیں زیادہ مطالعہ سے اُن کی ’’نثری فکر‘‘ کی کمزوریاں بھی نظرآئیں، خصوصاً اُن کے بعض اجتہادات جن کو آج اقبال کی اصل اسلامی فکراوراُن کی ’’روشن خیالی‘‘ کے ثبوت کے طورپرپیش کیاجاتا ہے جب کہ ’’جدیدترکی‘‘ کی جمہوریت سے اُن کی اثرپذیری کوبعض لوگ مرعوبیت کانام بھی دے سکتے ہیں، جب کہ یہ اُن کی حقیقی فکرنہ تھی۔ اپنے شعر میں توعلامہ نصیحت فرماتے ہیں:
گریز از طرز جمہوری غلامے پختہ کارے شو
کہ از مغز دو صد خر فکر انسانے نمی آید
اس طرح اوربھی کئی باتیں ہیں۔ اور مسائل پراُن کے اجتہاد نیم پختہ ہی محسوس ہوتے ہیں، تاہم شعرمیں اُن کی فکراکثر’’الہامی‘‘محسوس ہوتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ ’’آفاقی دانش‘‘ جو ایک ماورائی تصور ہے، اپنے اظہارکے لیے کسی کواپنا ذریعہ (medium) بنا لیتی ہے، چاہے وہ شخص اپنی عمومی ذہانت اورزندگی میں اُس معیار، افتاد اور کردار کا نہ ہو جیساکہ وہ اپنے کلام میں نظرآتاہے۔ بقول غالب:
آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں
غالب! صریرخانہ نوائے سروش ہے
لڑکپن میں دیوان حماسہ، متنبی اورمقامات بدیع الزمان ہمدانی اوراسی طرح کے عربی ادب کے کچھ حصے پڑھے تھے۔ فارسی میں گلستاں بوستاں اورکچھ غالب کا کلام(فارسی) پڑھا۔ وہ کتابیں جوعموماًمیرے بسترہوتی ہیں، کلیات اقبال اور دیوان غالب ہیں۔ ہندوستان میں جہاں ہمارے لیے کتابیں آسانی سے دست یاب نہ تھیں، والدصاحب نے اقبال کی ’’اسرارخودی‘‘ کی اچھے کاغذ کی ایک مجلد کاپی مجھے دی اورفرمایاکہ اس کتاب کونقل کرلو (فوٹوکاپی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی)۔ کچھ صفحات ابانے لکھے اوربیشترمیں نے، اس طرح اقبال کے فارسی کلام کی کچھ شدبد لڑکپن ہی میں ہو گئی تھی۔ ’’اسرار خودی‘‘ کاوالدصاحب نے اُردومیں ترجمہ کیا تھا۔ یہ اور’’رموزِخودی‘‘دونوں مجھے بے حدپسند ہیں۔ اقبال کی نظموں میں ’’شکوہ‘‘ اور جواب شکوہ‘‘، ’’مسجد قرطبہ‘‘ اور ’’سوزوساز‘‘، ’’طلوع اسلام‘‘ پسند ہیں۔ میرے خیال میں فکروفن کویکجا کر کے دیکھا جائے تو محمد اقبال دنیاکے سب سے بڑے شاعر ہیں، کم ازکم اُردو اور انگریزی شاعری میں جس کا کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے۔ غالب، ذوق، داغ اور میرکی کچھ غزلیں (کلیات میرکودیکھ کر مایوسی ہوئی) اور نئے شعرا میں فیض احمد فیض (جوش کے ہاں الفاظ کا شکوہ اورجادو زیادہ ہے)۔ انگریزی شاعری عموماً پھیکی اورطفلانہ محسوس ہوتی ہے۔ شیکسپےئرکے کئی ڈرامے پڑھے، لیکن اس کاجولیس سیریز مجھے اچھالگا۔
حالی کی مسدس مدوجزراسلام، اس کاکافی حصہ بچپن میں زبانی یادتھا۔خصوصا یہ نعتیہ اشعار
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی برلانے والا
میرے خیال میں اُردو کی بہترین نعتیہ شاعری میں شمارکیے جانے کے لائق ہیں۔
اپنے فکری تضادات کا مجھے اعتراف ہے۔ ایک طرف توروایتی علما میں مولانا اشرف علی تھانوی، (ان کی’’ بہشتی زیور‘‘ ہمارے ہاں جہیز میں ضرور دی جاتی تھی اور میراخیال تھاکہ اس طرح کی کوئی کتاب یا اس کا کوئی نظرثانی شدہ/ترمیم شدہ ایڈیشن اب بھی اس مقصدکے لیے کارآمد ہوگا) پسند تھے اور دوسری طرف سرسید، ابوالکلام آزاد،مولانا مودودی، شبلی نعمانی، سیدسلیمان ندوی، گاندھی جی (تلاش حق)، علی شریعتی (On the Sociology of Islam, Hagerism) کارل مارکس، میکس ویبرجیسے مفکراور مصنف۔
مفکرین میں مجھے سقراط/افلاطون اور کانٹ نے متاثر کیا۔سقراط کی زندگی اورتعلیمات (اگراس میں سے افلاطون کے حشو وزوائد نکال دیے جائیں) پیغمبروں کی سی نظرآتی ہے۔کانٹ کے فلسفہ اخلاق کی اسلامی تعلیمات سے کافی مماثلت ہے۔ ان کے علاوہ جارج برکلے کی تصوریت پڑھنے میں مزاآتاتھا،اگرچہ میں نے اس کی’’نتائجیت‘‘کے فلسفے سے کبھی کلی طور پراتفاق نہیں کیا۔کارل مارکس اوراینجلزکے فلسفے کی تمام ترجزئیات سے مجھے اتفاق نہیں، لیکن میں انہیں عظیم (اور مخلص) فلاسفروں میں شمارکرتا ہوں۔میں نے مارکس کیCapitalکی پہلی جلد اورکئی دوسری تحریریں پڑھیں اوراُن سے متاثرہوا۔عصری مفکرین میں سی۔ڈبلیو،ملزکی تحریروں میں گہرائی اورسچائی محسوس کی۔کمرہ جماعت میں ایک دفعہ رُشدی کی The Satanic Versesکاذکرآیا۔ میں نے نہیں پڑھی تھی۔ایک طالبہ نے مجھے پڑھنے کو دی۔ غصہ تو کیا آتا، سچ تویہ ہے کہ یہ کتاب مجھ سے پوری پڑھی ہی نہیں گئی۔نہایت غیردلچسپ اور غیر معقول لگی۔مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ایک طرح کی شہرت اور’’پذیرائی‘‘ کیوں ہوئی۔
جوکتابیں اورتحریریں مجھے اچھی لگتی ہیں، میں چاہتاہوں کہ دوسرے بھی انہیں پڑھیں۔ اس کے لیے میں اکثروہ کتابیں، تحریریں اپنے عزیزوں اورحلقہ احباب میں دیتا ہوں یا انہیں متعارف کراتا ہوں۔ اگرتحریرچھوٹی ہو تواس کی تصویریں نقل دے دیتا ہوں۔ کتابیں تحفتاً بھی دیتا رہتا ہوں۔ ایک عرصے سے شادی اورخوشی کے دوسرے مواقع پر میں قرآن مجید (خصوصاً مولانا مودودی کی ’’ترجمانی‘‘ کے ساتھ) ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اب وہ CDs بھی تحفے میں دیتا ہوں جن میں قرآت قرآن مجیدکے ساتھ ساتھ مولانا کی تفسیر ’’تفہیم‘‘ ہے۔
میری تعلیم کا آغاز تو ہندوستان میں میرے والدمرحوم کی اُردواوراسلامیات کی کتابوں سے ہواتھا جواس وقت وہاں سکولوں میں مروج تھیں۔ میری خوش قسمتی اوراعزازتھاکہ پاکستان میں آکریہاں درسیات کی تدوین اورتالیف میں، میں نے ان کے ساتھ کچھ کام کیا۔حقیقت تویہ ہے کہ میں اُن کی فکراورفہم دین اوراسلوب زندگی سے سب سے زیادہ متاثرہوا۔ شیخ احمدسرہندیؒ سے اُنہی نے مجھے متعارف کرایا تھا اوراُن کی فکرپرکام کرنے کوآمادہ کیاتھا۔اُن کے دوست اورمیرے بزرگ ڈاکٹرغلام مصطفی خاںؒ نے مجھے حضرت مجددکے ’’مکتوبات‘‘کا مشہورامرتسرایڈیشن اوران کی کئی فارسی تحریریں دیں۔ کچھ کتابیں اس سلسلے کے ایک اوربزرگ حاجی محمداعلیٰ نے بھی عنایت کیں۔ میرے دوست خالد اسحق ایڈووکیٹ مرحوم نے مجھے اپنانہایت قیمتی اوربہت منظم کتب خانہ استعمال کرنے کی کھلی اجازت دی تھی اور میرے لیے ایک گوشہ مخصوص کرادیا تھا جہاں میں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے کی نوک پلک درست کی اوراسے تکمیل کو پہنچایا۔ خالد اسحق صاحب میرے خیال میں پاکستان یاشاید آج کی دنیا میں(خدابخش لائبریری) ٹپنہ کے استثنا کے ساتھ، جومیں نے نہیں دیکھی، سب سے بڑی نجی لائبریری رکھتے تھے۔ان کی خواہش تھی کہ یہ کتب خانہ کراچی ہی میں رہے اوریہاں لوگ اس سے مستفید ہوں، مگر ان کی وفات کے بعد(اُن کے قریبی دوست سعیدصاحب کی کوششوں کے علی الرغم) اُن کے بچوں کی مرضی سے کتابوں کایہ قیمتی ذخیرہ لاہورکے ایک تعلیمی ادارے کی تحویل میں چلا گیا۔
میرے پاس کتابوں کاکوئی بڑاذخیرہ تونہیں۔والدمرحوم کی وہ کتابیں ہیں جوہندوستان سے یہاں آسکیں۔چند سومیری کتابیں ہوں گی۔ ان میں شبلی،سیدسلیمان ندوی،مولانا مودودیؒ کی کتابیں،فلسفہ تاریخ اورمتفرق موضوعات پر کتابیں اور جرائد، دائرہ معارف اسلامیہ جیسی کتابیں شامل ہیں، لیکن اب کتابوں کو سنبھالنا مشکل ہوتاجارہاہے۔
میں عاریتاً کتابیں صرف ’’معتبر‘‘لوگوں ہی کو دیتا ہوں۔ تاہم محسوس ہوتاہے کہ میرے علم وایماکے بغیربھی بعض ’’شائقین‘‘ کتابیں لے جاتے ہیں اورواپس نہیں کرتے۔اس کاعلم اُس وقت ہوتا ہے جب اُس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ’’غائب پائی جاتی‘‘ہے۔ میری لکھی ہوئی بعض کتابیں بھی اب میرے پاس نہیں۔ ایک اہم کتاب جس کا اب بدل شاید نہ مل سکے، ’’تفہیم القرآن‘‘ (مولانا مودودی)کے پہلے ایڈیشن کی وہ پہلی جلد ہے جس پرخودمولانامودودیؒ اور پبلشر قمرالدین صاحب کے دستخط تھے۔ ایک صاحب ’’درس‘‘کے لیے گئے اورپھرواپس نہ آئی۔
معالعہ کے لیے کوئی مخصوص اوقات نہیں۔ جب بھی موقع مل جائے اورجو موزوں کتاب دست یاب ہو، پڑھ لیتا ہوں، لیکن رات سونے سے پہلے (بعض اوقات دیر تک)پڑھنے کی عادت ہے۔دن میں پڑھنے کی نشست عموماً میز، کرسی پراوررات میں بھی اس طرح یالیٹ کرمطالعہ کرتاہوں۔
عام تعلیم یافتہ افرادکے لیے میرامشورہ یہ ہے کہ وہ رات میں یادن کے فرائض میں سے جوقت وہ نکال سکیں، مطالعے کی عادت ڈالیں۔اخبارات اورہنگامی،وقتی تحریروں اورٹی وی پرزیادہ وقت صرف نہ کریں،اپنے محلے یا سہولت کے مقام پرکوئی کتب خانہ تلاش کریں جہاں کتابیں عاریتاً مل سکتی ہوں۔پرانی یااپنی کتاب کوتختہ مشق نہ بنائیں۔ اس پرکچھ لکھنے یانشان لگانے سے پرہیزکریں۔میں نے بعض اچھے کتب خانوں کی قیمتی کتابوں کودیکھا ہے کہ ان میں بعض ’’قارئین‘‘نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔اپنی قیمتی آرا درج کی ہیں اوربعض ظالموں نے ورق پھاڑ لیے یابلیڈ سے تراش لیے ہیں۔یہ بہت افسوس ناک ہے۔اخبارکابل کم کرکے کچھ رقم کتابوں پرصرف کریں۔ تفریحی ادب میں پہلے ہمارے کلاسیکی ادب کوپڑھنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی سنجیدہ علمی تحریروں کے لیے بھی وقت نکالیں۔ ادب عالیہ سے غیرمحسوس طورپر ہماری فکری رہ نمائی ہوتی ہے اوربالواسطہ طورپروہ ہمارے اخلاق وعادات پر اثرانداز ہوتا ہے۔ ہمارے رویوں کی تراش خراش کرتاہے اوراعلیٰ آفاق اقدارتک سہولت کے راستے لے جاتا ہے، جب کہ گھٹیا ’’بازاری ادب‘‘ فکشن، نثر اورشعر غیرمحسوس طریقے سے ہمیں ’’اسفل‘‘کے گڑھوں میں اُتارتاچلاجاتاہے اوراگراُس کی چاٹ پڑجائے توپھراس کے اثرات عام زندگی اوررویوں میں بھی نظرآنے لگتے ہیں۔
ایک عام قاری کے لیے ایک زمانے میں انگریزی میں کلاسیکی ادب (اور دوسری کتابیں) ’’پیپربیک‘‘ میں بہت ارزاں مل جاتی تھیں۔ پاکستان میں بھی بعض اشاعتی اداروں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن محسوس ہوتاہے کہ اب ایسا نہیں ہو رہا۔ اچھی کتابوں کے ارزاں ایڈیشن دست یاب ہوں گے توطلبہ اورعام لوگوں تک اُن کی رسائی ہوگی۔ اچھے غیرملکی ادب اورسنجیدہ علمی کتابوں کے تراجم کوبھی فروغ دینا چاہیے۔اس سلسلے میں جاپانی قابل تقلید ہیں۔وہاں کتابیں نہ صرف ارزاں ہیں بلکہ قابل ذکرکتابوں کے تراجم حیرت انگیزسرعت کے ساتھ بازارمیں آجاتے ہیں اوردلچسپی رکھنے والے افرادکوغیرملکی زبانوں سے محرومی کااحساس نہیں ہوتا۔ تقسیم ہند سے پہلے مرحوم حیدرآباددکن کی ریاست میں سرکاری سرپرستی میں جو دارالترجمہ قائم تھا، اس نے اُردو جاننے والوں کی وہ خدمت کی جس کی نظیرنہیں ملتی۔افسوس کہ پاکستان کی قومی زبان قرار دینے کے باوجود ہم اس کاعشرعشیربھی نہ کرسکے۔جامعہ کراچی کے شعبہ تصنیف وتالیف وترجمہ میں بھی زیادہ کام نہیں ہورہا۔یوں محسوس ہوتاہے کہ شعوری(غیرشعوری)طورپرہم اُردو کوختم کررہے ہیں۔ رسم الخط بدل کرانگریزی حروف میں اُردولکھی جارہی ہے۔ درسیات میں اعلیٰ جماعتوں کے لیے اُردو کتابیں دست یاب نہیں۔ انگلش میڈیم سکولوں کافروغ ہے اوراُردوصرف بول چال کی زبان بنتی جارہی ہے۔اچھے تعلیمی اداروں اور جامعات کے بچے اورنوجوان بھی اُردوکی علمی یاشعری زبان کوسمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ (یہ لطیفہ نہیں واقعہ ہے کہ ایک مشہوراعلیٰ تعلیمی ادارے کے ذہین اورصاحب ذوق نوجوان کومیں نے ’’بال جبریل ‘‘پڑھنے کے لیے کہا تووہ حیران تھا کہ حضرت جبریل کے’’مُوئے مبارک‘‘ کوایک کتاب کاعنوان کس طرح بنایا جاسکتا ہے؟)
میں کوشش کررہا ہوں کہ سکولوں اورکالجوں کے طلبہ کے لیے آٹھویں جماعت اورآگے کے لیے کچھ ایسی کتابوں کا انتخاب کروں جوہرجماعت میں(لازمی اوراختیاری مضامین کی کتابوں کے علاوہ) اُنہیں مہیاکی جائیں اورانہیں لازماً پڑھائی جائیں۔ اس طرح وہ نہ صرف اُردوزبان کے معیاری ادب سے آشنا ہوں گے، بلکہ اُنہیں اپنی اصل ثقافت، زبان اورتہذیب سے بھی موانست ہوگی۔ بدقسمتی سے آج بیشتراعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیرتعلیم نوجوان اوراساتذہ بھی اُردو اور اُردو ادب سے اتنے ہی واقف ہیں جتنا انہوں نے اپنی درسی کتاب میں پڑھ لیاہے۔اس کے علاوہ انہیں نہیں معلوم کہ ڈپٹی نذیراحمدکون تھے اورمرزافرحت اﷲ بیگ کون۔پنڈت رتن ناتھ سرشارکون تھے اورمیاں آزاداورخوجی صاحب کون ہیں۔ نانی عشوکون تھیں اورمرزا ظاہرداربیگ کون؟اپنے کلاسیکی ادب (اور نتیجتاً ثقافتی ورثے اوراقدار سے کٹ کر جو نئی نسل وجود میں آرہی ہے، اس کے ناخوش گوار اثرات بظاہرتوکچھ ابھی دیکھنے میں آرہے ہیں، لیکن میراخیال ہے کہ آئندہ اس کے بڑے نقصان ہوں گے کہ اس طرح ایسی قوم وجود میں آجائے گی جس کی نہ اپنی زبان ہوگی نہ اپنی ثقافت نہ اپناذخیرۂ اقدارنہ خیروشرکے لیے اپنا کوئی پیمانہ۔
قرآن کریم کے علاوہ تین کتابیں کون سی ہوں گی جومیں اپنے پاس رکھنا چاہوں گا؟یہ بہت مشکل سوال ہے۔ ہزاروں خواہشیں (یہاں کتابیں پڑھیے) ایسی کہ ہرخواہش .......۔ بہرحال میراخیال ہے کہ موطاامام مالک، سیرۃ النبی شبلی اور کلیات اقبال (اُردو وفارسی) ایسی تین کتابیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کتاب کی اور اجازت ہو جائے! Dialogues of Plato۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ افلاطون کے بعدبیشترفلسفہ اسی پرتبصرہ وتنقید ہے۔
کھنچیں میر تجھ ہی سے یہ خواریاں
محمد اظہار الحق
(۱)
یہ ریاست ہاے متحدہ امریکہ کے شمال کا ایک شہر تھا جہاں اسے ملازمت ملی۔ ہجرت کر کے آنے کے بعد تارکین وطن کے سامنے یوں بھی امکانات کم ہی ہوتے ہیں۔ جہاں بھی روزگار مل جائے، وہیں سے آغاز کرنا پڑتا ہے۔ چند ہفتوں کے اندر ہی اسے احساس ہو گیا کہ پاکستانیوں کی تعداد وہاں کم ہے، بہت ہی کم۔ اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ قادیانی تھے جو مذہبی بنیادوں پر پناہ (Asylum) لے کر آباد ہوئے تھے۔ اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ ان کا مقاطعہ کرے، کسی تقریب میں جائے نہ ان سے میل ملاپ کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان لوگوں سے ملے اور جہاں، جب بھی موقع ہو، بات چیت کرے۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ تقاریب میں جاتا، دعوتوں میں شریک ہوتا اور تفریحی پروگراموں میں شرکت کرتا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ الگ نماز پڑھتا۔ یوں بھی ہوتا کہ وہ لوگ اپنی نام نہاد جماعت کرانے لگتے تو اسے دوسرے کمرے میں الگ سے جاے نماز خود ہی بچھا دیتے۔
چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن اسے ایک ٹیلی فون آیا۔ دوسری طرف ایک قادیانی نوجوان تھا۔ یہ تقاریب میں اسے ملتا رہتا تھا۔ اس نے اس کے گھر آنے کی اجازت چاہی۔ وقت مقرر کیا گیا۔ وہ نوجوان آیا، کئی گھنٹے گفتگو کرتا رہا۔ جاتے وقت اس نے پاکستان کے دو معروف علما کے ای میل ایڈریس جاننا چاہے اور یہ بھی کہا کہ اس کی اس ملاقات کا ذکر اس کی کمیونٹی کے کسی فرد سے نہ کیا جائے۔
چند ہفتوں کے بعد نوجوان پھر اس کے پاس آیا۔ اب کے نشست طویل تر تھی۔ اس دفعہ اس نے قادیانیت کے بارے میں گفتگو کی۔ اس کے خیالات اپنی کمیونٹی اور اپنے مذہب کے بارے میں ’’غیر روایتی‘‘ تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے پہلی بار یہ موقع میسر آیا ہے کہ ایک پڑھے لکھے اور مذہب کا علم رکھنے والے ایسے شخص سے گفتگو کر سکے جو اس کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ چند ملاقاتیں اور ہوئیں جن میں نوجوان سے کھل کر گفتگو ہوئی۔ آخر کار اس نے خالص دلائل کی بنیاد پر اقرار کیا کہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں تسلیم کرتا۔
یہ ایک سچا واقعہ ہے اور اس کے بیان میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی گئی۔ اس کے لکھنے کا سبب ماہنامہ ’الشریعہ‘ کا ستمبر ۲۰۱۱ء کا ایشو بنا ہے۔ اس پرچے میں کچھ مضامین اور خطوط ایسے ہیں جنھیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں مذہب کے نام لیوا کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کے رویے کیسے ہیں اور وہ اختلاف راے کا سامنا کرنے کے بجائے کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں!
سچی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو اس کے بعد اس سلسلے میں ایک نیا دور شروع ہونا چاہیے تھا۔ یہ دور سختی کا، مار دھاڑ کا، چیخ پکار کا اور لعن طعن کا نہیں، بلکہ ترغیب، تحریص اور تبلیغ کا ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانی پاکستان سے بھاگنے لگ گئے۔ آج وہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ گھٹن اور خوف کے ماحول کی بنیاد پر انھیں ہر جگہ پناہ (Asylum) مل رہی ہے۔ ان ملکوں میں چونکہ مذہبی آزادی ہے، اس لیے ان کی سرگرمیاں روز افزوں ہیں۔ سرکاری سطح پر فنڈ بھی مل جاتے ہیں، ان کے عبادت خانے بن رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں اور وہ پوری آزادی اور یکسوئی سے اپنے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ نئے آنے والے ’’پناہ گزینوں‘‘ (Asylum Seekers) کے لیے مدد اور رہنمائی کے مرکز کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔
اقلیت قرار دلوانے کے بعد پاکستان کے ان حلقوں کو جو قادیانیت کا تعاقب کر رہے تھے، اپنا کردار اور انداز بدل لینا چاہیے تھا۔ جو لوگ بیرون ملک رہ رہے ہیں یا رہے ہیں یا انھیں زیادہ سفر کرنے کے مواقع ملے ہیں اور انھوں نے قادیانیوں کے اندر جھانک کر دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قادیانی، بالخصوص ان کی نئی نسل، دو حوالوں سے جراحت پذیر (Vulnerable) اور اثر پذیر (Susceptible) ہے۔ ایک یہ کہ انھیں قادیانی عقائد کی تفصیل نہیں بتائی جاتی۔ اکثریت کو معلوم ہی نہیں کہ مرزا غلام احمد نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اس بے علمی پر تعجب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ قادیانی جماعت ایک ایسا بند گروہ (Cult) ہے جس کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ آمریت کایہ عالم ہے کہ ’’ارکان‘‘ کی زندگی کے ذاتی پہلو بھی باقاعدہ ’’اوپر‘‘ سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال ورجینیا میں چالیس قادیانیوں کو جماعت سے اس بنا پر خارج کر دیا گیا کہ انھوں نے کسی شادی کی تقریب کے دوران رقص کی محفل میں شرکت کر لی تھی۔ قادیانیوں کی نئی نسل اس حقیقت کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے نبی کو نبی نہ ماننے والے کافر ہیں۔ بالخصوص جو قادیانی نوجوان مغربی ملکوں کی آزاد اور انفرادی آزادی سے بھرپور فضا میں سانس لے رہے ہیں، ان کا رویہ اس ضمن میں قادیانیوں کی اس نسل سے بالکل مختلف ہے جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لندن میں بیٹھی اس گروہ کی ہیئت مقتدرہ حقائق کو نئی نسل سے چھپانے کی اور نئی نسل کو بے خبر رکھنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ قادیانیوں کا خاندانی نظام مربوط اور مضبوط برادری سسٹم پر قائم ہے۔ قادیانیت سے تائب ہونے والے شخص کے لیے، بالخصوص ایک نوجوان شخص کے لیے، اس مضبوط خاندانی نظام اور برادری کے جال سے نکلنا ازحدمشکل ہے۔
ان دونوں پہلووں کو سامنے رکھ کر ضرورت اس بات کی تھی کہ تبلیغ کے حوالے سے ایسی پالیسی بنائی جاتی کہ ایک طرف تو قادیانیوں کی نئی نسل کو اصلیت سے آگاہ کیا جاتا اور انھیں مطلع کیا جاتا کہ ان کے نام نہاد نبی نے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کہا ہے اورکون سی زبان استعمال کی ہے اور دوسری طرف ایسے ادارے بنائے جاتے جو قادیانیت سے تائب ہونے والے لوگوں کو سماجی اور مالی سہارا دیتے اور انھیں برادری کو خیر باد کہنے کا حوصلہ ہوتا۔ یہ سارا مسئلہ جوش سے زیادہ ہوش کا متقاضی تھا۔ قادیانیت کے عقائد غیر منطقی ہیں اور ان کی بنیاد اس قدر کمزور ہے کہ اگر ختم نبوت کے محافظین اور مجاہدین قادیانیوں کی نئی نسل کو قریب لانے کی کوشش کرتے تو یہ گروہ برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا، لیکن سختی، شور وغوغا، حکمت اور تدبر کی کمی اور مار دھاڑ نے ایک طرف تو ان کی نئی نسل پر منفی رد عمل طاری کر کے اسے اس بے بنیاد مذہب پر پختہ کر دیا اور دوسری طرف ان پر نوکریوں اور دیگر حقوق کے دروازے بند کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یوں کُبّے کو لات لگی اور پاکستان سے باہر کی دنیا میں ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے شہر سے باہر، مجرا کرنے والوں کی الگ تھلگ بستی پر صالحین ڈنڈے اور سوٹے لے کر پل پڑیں اور مجرا کرنے والی طوائفیں بھاگ کر محلوں اور گلی کوچوں میں ٹھکانے بنا لیں جہاں انھیں پہچاننا ممکن ہو نہ نکالنا۔
اس ضمن میں اصل مقصدیہ ہونا چاہیے تھاکہ دامے درمے سخنے قادیانیوں کو واپس اسلام کی طرف لایا جائے، لیکن بدقسمتی سے مکمل مقاطعہ کی پالیسی اپنائی گئی۔ سارا زور Non-issues (غیر اہم معاملات) پر دیا گیا۔ مثلاً گزشتہ سال جب لاہور میں قادیانیوں کی عبادت گاہ پر بم کا دھماکہ ہوا جس میں ستر افراد ہلاک ہوئے تو میاں نواز شریف نے ایک سیاسی بیان میں کہا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ نواز شریف کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر انھوں نے سیاست دان ہونے کے حوالے سے کہہ دیا تو یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا جس پر ہنگامہ برپا کر کے وقت اور وسائل ضائع کیے جاتے۔ تقسیم سے پہلے جب مسلمان، ہندو اور سکھ اکٹھے رہتے تھے تو بھائی بہن کے الفاظ کا استعمال عام تھا۔ مسلمان بچے ہندو اور سکھ خواتین کو محلوں اور گلیوں میں خالہ کہتے تھے، سہیلیاں بہنیں بنی ہوئی تھیں اور ہندو اور سکھ بابے مسلمان بچوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا تھاکہ اسلام پر آنچ آ رہی ہے۔
ان سطور کے لکھنے والے کو یقین ہے کہ ہمارے عقاب (Hawks) اس پر شدید گرفت کریں گے اور لکھنے والے کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، لیکن اس کے باجود حقیقت یہی ہے کہ یہ نان ایشوز ہیں۔ان معاملات پر طوفان کھڑا کر کے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔
یہاں ایک لطیفہ نما واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے سینئر دوست او رمعروف سفر نامہ نگار جناب مستنصر حسین تارڑ نے بیجنگ کے ایک ریستوران کا حال لکھا کہ ان کے چینی رہنما نے، جو اردو بولنے پر دسترس رکھتا تھا، ایک خاص ڈش کھانے سے منع کیا کہ یہ گدھے کا گوشت ہے۔ تارڑ صاحب نے کہاکہ وہ فلاں فلاں اصحاب تو کھا رہے ہیں۔ اس پرچینی گائیڈ نے جواب دیا کہ ہاں، وہ کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گدھے ہی کا گوشت ہے۔ غیر اہم معاملات کے دفاع میں شور قیامت بھی برپا کر دیا جائے تو پھر بھی وہ غیر اہم ہی رہیں گے۔
اس پس منظر میں الشریعہ کے مدیر محمد عمار خان ناصر کی وہ سطور دیکھیے جن پر الشریعہ کے ستمبر کے شمارے میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے:
’’قادیانی قیادت اور ان کے تاویلاتی جال میں پھنس جانے والے عام سادہ لوح مسلمانوں کے مابین جو فرق حکمت دین کی رو سے ملحوظ رکھا جانا ضروری تھا، وہ نہیں رکھا گیا اور عام لوگوں کو ہمدردی اور خیر خواہی سے راہ راست پر واپس لانے کے داعیانہ جذبے پر نفرت اور مخاصمت کے جذبات نے زیادہ غلبہ پا لیا۔ میرے نزدیک قادیانی گروہ کو قانونی طور پر مسلمانوں سے الگ ایک غیر مسلم گروہ قرار دے دیے جانے سے امت مسلمہ کے تشخص اور اس کی اعتقادی حدود کی حفاظت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے علما اور داعیوں کی محنت اور جدوجہد کا ہدف اصلاً یہ ہونا چاہیے کہ وہ دعوت کے ذریعے سے ان عام قادیانیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے حوالے سے قادیانی قیادت کا مفاد بھی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں سے الگ تھلگ اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ناواقف رہیں اور معلوم نہیں کن ضرورتوں یا مجبوریوں کے تحت ہماری مذہبی قیادت بھی انھیں مسلمانوں سے دور ہی رکھنے کو اپنی ساری جدوجہد کا ہدف بنائے ہوئے ہے۔ ‘‘
اس تحریر میں کون سی چیز خلاف اسلام ہے یا قادیانیوں کے حق میں ہے جس کی بنیاد پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے؟ اس افسوس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے!
(۲)
ستمبر ہی کے شمارے میں مولانا زاہد الراشدی کا مضمون ’’دینی جدوجہد اور اس کی اخلاقیات‘‘ ہماری اوپر لکھی ہوئی گزارشات کی تصدیق کر رہا ہے۔ قادیانیت کے ضمن میں تیر وہاں برسائے جا رہے ہیں جہاں ہدف نہیں ہے۔ یہ رویہ Don Quixote کی یاد دلاتا ہے جو ہوا میں تلواریں لہرانے والا ہیرو تھا۔ قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہو جانے والے شخص کو قادیانی کہنا اور پھر اس پر اصرار کرنا، اور مولانا منظور احمد چنیوٹی جیسے انتہائی سینئر اور بزرگ عالم دین کا محض سنی سنائی بات پر مسلمان افسروں کو قادیانی قرار دینا اس حقیقت کا غماز ہے کہ ہمارے علماء کرام اس ضمن میں ایک ایسی انتہا پر جا پہنچے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے صریحاً متحارب ہے۔
یَا أَیُّہَا الَّذِیْنَ آمَنُوا إِن جَاءَ کُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیْبُوا قَوْماً بِجَہَالَۃٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِیْنَ (الحجرات ۴۹:۶)
’’اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمھارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کرلیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو۔ پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔‘‘
رہی بلیک میلنگ کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے مسلمان کو قادیانی کہہ دینا، جیساکہ ایک مولوی صاحب نے مولانا زاہد الراشدی کی موجودگی میں کیا، تویہ بہت سے پیشہ ور مولوی حضرات کا معمول ہے۔ مرکزی اور صوبائی دار الحکومت میں باقاعدہ ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جو جمعے کے خطبے کی دھمکی دے کر بیوروکریسی سے کام نکلواتے ہیں اور کام نہ ہونے کی صورت میں منبر ومحراب اور آلہ مکبر الصوت سمیت ساری سہولتیں جو دین حق پھیلانے کے لیے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے حاصل کی گئی ہیں، ’’مجرم‘‘ کو ’’سزا‘‘ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ چند دلچسپ واقعات اس فقیر کے علم میں بھی ہیں۔
(۳)
ستمبر کے ’الشریعہ‘ میں خاصے کی چیز ایک خط ہے جو حافظ صفوان محمد کے مضمون ’’سماجی، ثقافتی اور سیاسی دباؤ اور دین کی غلط تعبیریں‘‘ (الشریعہ، جولائی ۲۰۱۱ء) کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اس خط کے چند فقرے ملاحظہ کیجیے:
’’حافظ صفوان کس بنیاد پر اپنا قد بڑھانے کے لیے یہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں۔‘‘
’’شراب کی بوتل پر زم زم کا لیبل چپکانا اور سور کے گوشت کوبکری کے گوشت سے تعبیر کرنا .......‘‘
’’..... یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے طرز فکر کو اپنانے جیسا فعل ہے۔‘‘
’’فکری وذہنی انتشار کی عکاس یہ طویل تحریر پڑھ کر صفوان چوہان صاحب کے ژولیدہ فکر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔‘‘
’’..... انھوں نے جو دست تطاول درازکیا ہے، یہ ان کے چرغینہ پن پہ دلالت کرتا ہے۔‘‘
’’انھوں نے جس چترائی سے دینی حلقوں پہ ہاتھ صاف کیا ہے۔‘‘
’’یہ گھناؤنا انداز اور یہ پھکڑ بازیاں کس مکروہ اور کثیف سوچ کی عکاس ہیں۔‘‘
’’آپ اپنا ہودہ و بے ہودہ ان کے نام منسوب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واہیات ارشاد فرمانے ہی ہیں تو براہ کرم کسی اور کندھے کو تلاش کیجیے۔ الفاظ آپ کے، سوچ آپ کی اور منسوب کر رہے ہیں سید ذوالکفل بخاری شہید کی طرف! یہ دوست کشی اور محسن کشی کی انتہا ہے۔‘‘
’’آپ کے مضمون کی ہر سطر کا ہر لفظ شاہد عدل اور شاہد اہل ہے کہ نہ تو آپ کو مذہب کے بارے میں مطالعے کا موقع ملا ہے اورنہ ہی تاریخ سے آپ کو کچھ مس ہے۔‘‘
’’آپ تو نرے پروفیسرو ڈاکٹر ہیں، بلکہ اب تو اِس دال میں بھی کچھ کالا محسوس ہوتا ہے۔‘‘
’’پرویز مشرف اور آپ کی سوچ میں کتنی مماثلت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔‘‘
’’یہ واہیات لفظ چیخ چیخ کر پکاررہاہے کہ آپ ہی کے دہن شریف سے نکلا ہے۔‘‘
’’شریعت اور قانون میںیہ در اندازی انتہائی واہیات ہے۔‘‘
جنابِ من! اپنی حیثیت کا تعین کر لیجیے۔
’’ایسی واہیات اور مکروہ باتیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کی روح مبارکہ کو اذیت تو نہ پہنچائیں۔‘‘
اگر شمار کرنے میں غلطی نہیں ہوئی تو اس خط میں واہیات کا لفظ چار مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ہمیں نہیں معلوم کہ جس خط میں دلیل ایک بھی نہیں دی گئی اور واہیات، سور کا گوشت، چرغینہ پن، چترائی، پھکڑ بازیاں، ہودہ وبے ہودہ جیسے الفاظ بار بار استعمال کیے گئے ہیں، اس کی اشاعت ایک دینی پرچے میں کیوں ضروری تھی اور اس کے شائع نہ ہونے سے کون سی صحافتی اقدار مجروح ہو رہی تھیں، لیکن اس سے قطع نظر، اس خط میں حافظ صفوان محمد پر ایک انتہائی سنجیدہ الزام لگایا گیا ہے۔ مکتوب نگار نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ’’اپنا ہودہ وبے ہودہ‘‘ اور ’’واہیات اور مکروہ باتیں‘‘ سید ذو الکفل بخاری مرحوم کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ امکانات دو ہی ہیں۔ اگر مکتوب نگار سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ صفوان محمد نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو مکتوب نگار نے حافظ صاحب پر بہتان باندھا ہے۔
مکتوب نگار کو میں نہیں جانتا۔ہاں حافظ صفوان محمد مجھے ہمیشہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان لگے ہیں۔ تاہم سید ذوالکفل بخاری مرحوم اس گنہ گار کے بھی دوست تھے۔ میں ملتان جب بھی گیا، ان سے ضرور ملاقات ہوئی۔ میرے اعزاز میں انھوں نے اپنے گھر چند بار دوستوں کو جمع کر کے ملاقات کو تقریب کی شکل بھی دی۔ کئی بار ملنے ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس تشریف لائے تو مشہور شاعر خالد مسعود خان بھی ان کے ساتھ تھے۔
۲۰۰۹ء کے وسط میں، میں ایک تقریب کے سلسلے میں جدہ گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچا تو شاہ صاحب میرے منتظر تھے۔جتنی دیر میں عمرہ میں مصروف رہا، وہ حرم ہی میں رہے۔ بعد میں انھوں نے کے ایف سی سے مجھے کھانا کھلایا۔ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حرم سے نکل رہے تھے تو معروف شاعر انور مسعود بھی مل گئے۔ وہ سید ذو الکفل بخاری سے ان کے نانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ ذو الکفل نے عطاء اللہ شاہ بخاری کا وہ لازوال فقرہ سنایا جو انھوں نے علی گڑھ میں تقریر کرتے ہوئے اردوے معلی میں فرمایا تھا: ’’برس دن گزرے ......‘‘۔ افسوس کہ مجھے فقرے کا آخری حصہ یاد نہیں رہا۔ انور مسعود اس پر بہت دیر تک سر دھنتے رہے۔ میں سہ پہر کو جدہ واپس چلا گیا۔ اسی شام یا اگلی شام شاہ صاحب خاص طور پر میری حوصلہ افزائی کے لیے جدہ تشریف لائے اور تقریب میں شرکت کی۔ اس شام کی ایک یادگار تصویر بھی ہے جس میں ذو الکفل کے ساتھ میں، افتخار عارف اور مختار علی کھڑے ہیں۔ مختار علی خطاط اور شاعر ہیں اور ملتان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے شاہ صاحب کے ساتھ خصوصی مراسم رکھتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ تصویر مختار علی نے فیس بک پر بھی لگائے رکھی۔
جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ۲۰۰۹ء کے اوائل میں سید ذو الکفل بخاری مرحوم اسلام آباد تشریف لائے تو ایک رات میرے ہاں قیام فرمایا۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو اسی شام معروف صحافی ہارون الرشید بھی تشریف لائے اور کافی دیر محفل برپا رہی۔غالباً دوسرے دن صبح انھوں نے باتوں باتوں میں اپنے کسی دوست یا عقیدت مند کا ذکر کیا جو ایک ملازمت اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے کہ اس میں کوٹ پتلون پہننا پڑتا تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ انھوں نے ان صاحب کو تلقین کی کہ وہ یہ ملازمت ضرور کریں۔ ظاہر ہے،مجھے ان کا ارشاد لفظ بہ لفظ یاد نہیں، لیکن جو کچھ انھوں نے کہا، اس کا واضح مطلب یہ تھاکہ کوٹ پتلون پہنناکوئی غیر اسلامی حرکت نہیں۔
حافظ صفوان محمد پر عورتوں کی دکانداری کرنے، عورتوں کے مسجد میں آ کر نماز باجماعت میں شریک ہونے اور ’’اسلامی‘‘ لباس کے ’’تمسخر اڑانے‘‘ کے حوالے سے اعتراض ہوا ہے، اگرچہ دلیل کوئی نہیں دی گئی۔اس میں دلچسپ ترین مسئلہ لباس یا اسلامی لباس کا ہے۔ اسلامی لباس کی آج تک کوئی تعریف نہیں کی جا سکی۔رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، وہ وہی لباس پہننا جاری رکھتے تھے جو قبول اسلام سے پہلے پہنتے تھے۔ آپ نے لباس کے بنیادی اصول، ستر کے لحاظ سے مقرر فرمائے، لیکن کسی لباس کی تخصیص نہیں فرمائی۔ اس ضمن میں مولانا محمد منظو رنعمانی ؒ نے بہت دل نشین پیرایے میں وضاحت کی ہے۔
’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں ان حدود واحکام کی پابندی کے ساتھ جو مذکورہ بالا احادیث* سے معلوم ہو چکے ہیں، اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے جس طرح اور جس وضع کے کپڑوں کا اس زمانے میں آپ کے علاقے اور آپ کی قوم میں رواج تھا۔ آپ تہبند باندھتے تھے،چادر اوڑھتے تھے،کرتا پہنتے تھے، عمامہ اور ٹوپی بھی زیب سر فرماتے تھے اور یہ کپڑے اکثر وبیشتر معمولی سوتی قسم کے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی دوسرے ملکوں اور دوسرے علاقوں کے بنے ہوئے ایسے بڑھیا کپڑے بھی پہن لیتے تھے جن پر ریشمی حاشیہ یا نقش ونگار بنے ہوتے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھی بہت خوش نمایمنی چادریں بھی زیب تن فرماتے تھے جو اس زمانے کے خوش پوشوں کا لباس تھا۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ زبانی ارشادات وہدایات کے علاوہ آپ نے امت کو اپنے طرز عمل سے بھی یہی تعلیم دی کہ کھانے پینے کی طرح لباس کے بارے میں بھی وسعت ہے۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کے ساتھ ہر طرح کا معمولی یا قیمتی لباس پہنا جا سکتا ہے اور یہ کہ ہر علاقے او رہر زمانے کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ شرعی حدود واحکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا علاقائی وقومی پسندیدہ لباس استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے ان اصحاب صلاح وتقویٰ نے بھی جن کی زندگی میں اتباع سنت کا حد درجہ اہتمام تھا، یہ ضروری نہیں سمجھا کہ بس وہی لباس استعمال کریں جو رسول اللہ استعمال فرماتے تھے۔ دراصل لباس ایسی چیز ہے کہ تمدن کے ارتقا کے ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس طرح علاقوں کی جغرافیائی خصوصیات اور بعض دوسری چیزیں بھی لباس کی وضع قطع اور نوعیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کا لباس یکساں ہو یا کسی قوم یا کسی علاقے کا لباس ہمیشہ ایک ہی رہے۔ اس لیے شریعت نے کسی خاص قسم اور خاص وضع کے لباس کا پابند نہیں کیا ہے۔ ہاں، ایسے اصولی احکام دیے گئے ہیں جن کی ہر زمانے میں ہر جگہ بہ سہولت پابندی کی جا سکتی ہے۔‘‘ (معارف الحدیث، حصہ ششیم، صفحہ ۴۲۴)
ہمارے علماء کرام جو لباس زیب تن فرماتے ہیں، وہ اس علاقے کا یعنی برصغیر اور افغانستان کا لباس ہے۔ مشرقی بھارت، بنگلہ دیش ، ملایشیا اور انڈونیشیا کے مسلمان جو لنگی (تہمند) باندھتے ہیں، برما کے غیر مسلم بھی وہی پہنتے ہیں بلکہ یہی لنگی برما کا قومی لباس ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کا اصرار کہ پتلون پہننا ناجائز یا غیر اسلامی لباس ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر الاسکا یا نیوزی لینڈ کا کوئی باشندہ اسلام قبول کرے تو کیا وہ پتلون پہننا چھوڑ دے؟ اور اگر ایسا کرے تو وہ کون سا لباس پہنے؟ وہ لباس جو عرب علما پہنتے ہیں؟ یا وہ جو افغانستان یا پاکستان کے علما پہنتے ہیں؟ یا وہ جو بنگلہ دیش کے یا ملایشیا کے علماء کرام پہنتے ہیں؟ دوسری طرف حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے، انھوں نے طیلسان کا بنا ہوا ایک کسروانی جبہ نکال کر دکھایا۔ اس کا گریبان ریشمی دیباج سے بنوایا گیا تھا اور دونوں چاکوں کے کناروں پر بھی دیباج لگا ہوا تھا۔ حضرت اسماءؓ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے۔ یہ میری بہن عائشہ صدیقہؓ کے پاس تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے لے لیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے اور اب ہم اس کو مریضوں کے لیے دھوتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔
دین کے نام پر لوگوں پر ایسی پابندیاں عائد کرنا جن کا حکم اللہ نے دیا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا رویہ ہے جسے نرم ترین الفاظ میں بھی غلط ہی کہا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ملک کے ایک کثیر الاشاعت روزنامے میں ایک معروف عالم دین ہر جمعہ کے روز سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے سوال پوچھا۔ مولانا نے جواب میں اسے بدعت قرار دیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عرب میں میز کرسی کا وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت صوفہ سیٹ، فوم والے بیڈ، ایئر کنڈیشنر، ہوائی جہاز، ٹیلی ویژن، موبائل فون اور لاؤڈ اسپیکر کا وجود بھی نہیں تھا۔کار،بجلی اور گیس بھی نہیں تھی۔ پھر صرف میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہی کیوں بدعت ہو؟ میر تقی میر نے یہ شعر کہتے وقت ضرور کانوں کو ہاتھ لگایا ہوگا۔
کھنچیں میر تجھ ہی سے یہ خواریاں
نہ بھائی ہماری تو قدرت نہیں
حواشی
* یہ احادیث ان موضوعات کے بارے میں ہیں: عورتوں کے لیے زیادہ باریک لباس کی ممانعت، لباس میں تفاخر اور نمائش کی ممانعت، مردوں کے لیے ریشم اور سونے کی اور شوخ سرخ رنگ کی ممانعت، مردوں کو زنانہ اور عورتوں کو مردانہ لباس کی ممانعت۔
چند بزرگ علماء کا انتقال
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
گزشتہ دنوں چند محترم دوست اور بزرگ علمائے کرام انتقال کر گئے جن کی جدائی کا صدمہ ہمارے دینی وعلمی حلقوں میں مسلسل محسوس کیا جارہا ہے۔
- شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ملک کے علمی ودینی حلقوں کے لیے صدمہ ورنج کا باعث بنا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر بزرگوں میں سے تھے جنھوں نے پون صدی قبل گوجرانوالہ میں توحید وسنت کے پرچار اور علماء دیوبند کے مسلک کے فروغ وتعارف میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحبؒ نے ۸۰ برس سے زیادہ عمر پائی اور زندگی بھر دینی علوم کی تدریس وترویج میں مصروف رہے۔ ۱۹۷۷ء میں انھوں نے قلعہ دیدار سنگھ کے حلقہ سے جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کی طرف سے پاکستان قومی اتحاد کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی حصہ لیا۔ وہ دینی تحریکات میں ہمیشہ سرگرم رہے اور ان کے ہزاروں تلامذہ ملک کے مختلف حصوں میں دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انھیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور پس ماندگان اور سوگواروں کو صبر جمیل کی توفیق سے نوازیں۔ آمین یا رب العالمین۔
- حضرت مولانا محمد الطافؒ جمعیۃ علماء اسلام کے بزرگ راہ نماؤں میں سے تھے جن کا گزشتہ دنوں حافظ آباد میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق وادی سکیسر کے گاؤں کوٹلی سے تھا۔وہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل تھے اورحضرت السید مولانا محمد یوسف بنوریؒ کے شاگرد تھے۔ ۱۹۶۱ء میں حافظ آباد آئے، مرکزی جامع مسجد قدیم کی خطابت سنبھالی اور مدرسہ اشرفیہ قرآنیہ میں تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ وہ جید عالم دین، بے باک خطیب، تجربہ کار مدرس اورمنجھے ہوئے سیاسی راہ نما تھے۔ انھوں نے حضرت درخواستی، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا مفتی محمود اور حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کے ساتھ مسلسل جماعتی محنت کی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمن کے ساتھ پورے عزم واستقامت کے ساتھ وابستہ رہے۔ انتہائی نیک، خدا ترس اور حق گو بزرگ تھے۔ طویل علالت کے بعد ۸۰ برس کے لگ بھگ عمر میں انھوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین۔
- مولانا سید عبدالمالک شاہ میرے بہت پرانے دوست اور ساتھی تھے، جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں استاذ الحدیث تھے اور جمعیت علماء اسلام کے سرگرم راہ نماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کا تعلق مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے گاؤں سے تھا اور وہ مفتی صاحب کے معتمد کارکنوں میں سے تھے۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے تعلیم حاصل کی اور اسی دور میں جمعیت طلباء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کی تحریکی سرگرمیوں کا حصہ بن گئے۔ حضرت والد محترم اور حضرت صوفی صاحب کے ساتھ گہری محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ میرا ان کے ساتھ پہلا تعارف غالباً ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت کے دوران ہوا اور پھر یہ تحریکی رفاقت زندگی بھر جاری رہی۔ جمعیت علماء اسلام میں ہم نے ایک عرصے تک اکٹھے کام کیا، حتی کہ جب حضرت مفتی صاحب کی وفات کے بعد جمعیت علماء اسلام دو حصوں میں بٹی تو ہم دونوں ایک دوسرے کے مخالف کیمپوں میں تھے، مگر باہمی روابط، دوستی اور تعاون میں اس دور میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔وہ ان دنوں مدرسہ انوار العلوم میں مدرس تھے اور میں مرکزی جامع مسجد کا خطیب ہوں۔ وہ اپنے کیمپ کے لیے متحرک تھے اور میں اپنے کیمپ کے لیے متحرک تھا۔ وہ ایم آر ڈی میں تھے اور میں اس کا شدید مخالف تھا، لیکن اس باہمی محاذ آرائی کے دور میں بھی متعدد بار ایسا ہوا کہ پولیس ان کی تلاش میں ہوتی اور وہ میرے دفتر کے عقبی کمرے میں پناہ گزین ہوتے تھے۔
۱۹۷۵ء میں مسجد نور گوجرانوالہ کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں دیے جانے کے فیصلے کے خلاف عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس تحریک کو منظم کرنے اور مربوط طورپر چلانے میں مولانا سید عبدالمالک شاہ، ڈاکٹر غلام محمد، نوید انور نوید ایڈووکیٹ مرحوم، صوفی رستم علی قادر اور علامہ محمد احمد لدھیانوی سب سے زیادہ متحرک رہے۔ انھی کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں تحریک کامیاب ہوئی اور حکومت کو مسجد نور اور مدرسہ نصرۃ العلوم کو تحویل میں لینے کا نوٹیفکیشن واپس لینا پڑا۔ اس لحاظ سے شاہ صاحب مدرسہ نصرۃ العلوم کے محسن بھی تھے کہ ان کی شبانہ روز محنت اس مسجد ومدرسے کی آزادی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بنی۔
وہ گزشتہ کم وبیش پندرہ سال سے جامعہ نصرۃ العلوم کے استاذ تھے اور دورۂ حدیث میں عام طورپر مسلم شریف ان کے زیر درس رہتی تھی، جبکہ علوم وفنون کی دیگر کتابیں بھی انہوں نے مسلسل پڑھائیں اور ایک محنتی اور کامیاب مدرس کے طورپر شہرت حاصل کی۔ جمعیت علماء اسلام اور مولانافضل الرحمن کے ساتھ ان کا تعلق اور وفاداری قابل ذکر، بلکہ قابل رشک تھی۔ مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے یہ ساتھ نبھایا اور خوب نبھایا۔ وہ ایک عرصے سے بیمار تھے، شوگر کی وجہ سے ان کے ایک پاؤں کا انگوٹھا چند سال قبل کاٹنا پڑا تھا، مگر اس موذی مرض نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ گزشتہ دنوں ڈاکٹروں نے ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی اور اس کا علاج چل رہا تھا کہ معدے نے کام چھوڑ دیا۔ حوصلہ مند آدمی تھے، بیماری اور معذوری کے باوجود جماعتی اور مسلکی کاموں میں ہمیشہ متحرک رہے۔
بیماری کے ایام میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ان کا جنازہ مولانا فضل الرحمن پڑھائیں اور کوشش کی جائے کہ انہیں قبر کے لیے گوجرانوالہ کے بڑے قبرستان میں حضرت مولاناصوفی عبدالحمید سواتی کے قریب جگہ مل جائے۔ مولانا فضل الرحمن تو انتہائی کوشش کے باوجود جنازے تک نہ پہنچ سکے اور نمازہ جنازہ حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی مدظلہ نے جامعہ نصرۃ العلوم میں رات کے دس بجے پڑھائی، البتہ قبر کی جگہ انہیں حسب خواہش حضرت صوفی صاحب کے قدموں میں اور اپنے پرانے ساتھی مولانا اللہ یار خان کے پہلو میں مل گئی۔ جنازے میں مولانا عبدالغفور حیدری شریک ہوئے، جبکہ مولانا فضل الرحمن اگلے روز صبح تعزیت کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں اور ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطافرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ - مولانا میاں عبدالرحمن کا تعلق بالاکوٹ کے علاقے سے تھا۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم نے لاہور کے معروف بازار انارکلی میں ڈیرہ لگایا اور عمر بھر وہاں حق کی آواز بلند کرتے رہے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اور جمعیت علماء اسلام کے سرگرم راہ نماؤں میں سے تھے۔ ان کے مزاج میں حق گوئی دبدبہ ہر شخص محسوس کرتا تھا اور ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا لقب بھی مولانا محمد ابراہیم ڈنڈے والے پڑگیا تھا۔ انارکلی بازار کی مسجد کے دروازے پر ایک چھوٹی سی دکان میں، جسے دکان کہنا بھی شاید مبالغہ ہو، شہد کا ہلکا پھلکا کاروبار کرتے تھے اور عزت وآبرو کے ساتھ حق گوئی کا پرچم بلند رکھتے تھے۔ مولانا میاں عبدالرحمن ان کے فرزند اور جانشین تھے اور انہی کے اوصاف اور روایات کے امین تھے۔ جامعہ مدینہ کریم پارک سے تعلیم حاصل کی، حضرت مولانا سید حامد میاں اور حضرت مولانا عبیداللہ انورسے ارادت کا گہرا تعلق تھا اور جمعیت علماء اسلام کی دینی وسیاسی جدوجہد ان کی ہمیشہ جولان گاہ رہی۔ مجھے باپ بیٹا دونوں کی شفقت ومحبت ہمیشہ حاصل رہی اور خصوصی دعاؤں کے ساتھ جماعتی کاموں میں سرپرستی اور معاونت سے بھی بہرہ ور فرماتے تھے۔ لاہور کے دینی اجتماعات میں اکثر وبیشتر ان سے ملاقات ہوتی تھی اور وہ اپنے مسلک کے تمام حلقوں کو یکساں طورپر نوازتے تھے۔ ا نہیں لاہور کے دینی حلقوں میں دینی تحریکات کے سرپرست کے طورپر پہچانا جاتا تھا اور وہ ہر دینی تحریک اور مسلکی جدوجہد میں پیش پیش نظر آتے تھے۔
گزشتہ جمعرات کو ایک سفر کے دوران یہ اطلاع ملی مولانا میاں عبدالرحمن مانسہرہ میں ایک دینی اجتماع میں شرکت کے بعد واپس جاتے ہوئے ٹریفک حادثہ کا شکار ہوکر شہید ہوگئے ہیں۔ ایک مشفق دوست اور مخلص جماعتی ومسلکی راہ نما کی اچانک اور حادثاتی وفات پر بے حد صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، یا رب العالمین۔
مکاتیب
ادارہ
(۱)
بخدمت حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
الشریعہ کے اکتوبر ۲۰۱۱ کے شمارے میں ’’توہین رسالت کی سزا پر جاری مباحثہ ۔ چند گزارشات‘‘ کے عنوان کے تحت آپ نے مجلہ صفدر شمارہ ۶ میں شائع شدہ میرے تبصرے پر بھی کچھ اظہار خیال کیا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کم از کم میرے مضمون کو بالکل نہیں سمجھ پائے۔
’’توہین رسالت کا مسئلہ‘‘ کے نام سے عمار خان صاحب نے ایک کتاب لکھی جس میں انھوں نے اپنا موقف یہ ظاہر کیا کہ توہین رسالت کے جاری کردہ قانون کو جو کہ سزاے موت ہے، جب ذمی پرمنطبق کریں تو وہ قانون فقہ اسلامی سے مطابقت نہیں رکھتا اور حکمت ومصلحت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قتل ایک تو انتہائی درجے کی سزا ہے جو صرف اس وقت لاگو ہو سکتی ہے جب توہین رسالت کا مرتکب ذمی اس سے کسی طرح باز نہ آئے اور اعلانیہ اس کو اپنی روش بنا لے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں ہلچل مچ جائے۔ جب تک ذمی اس انتہا کو نہ پہنچے، اس کی سزا کے بارے میں فقہاے اسلام کے مابین اختلاف راے ہے۔ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اس جرم کی سزا ہر حال میں یہ ہے کہ مجرم کو قتل کیا جائے، جبکہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق فقہاے احناف کا رجحان یہ ہے کہ عام حالات میں اس جرم پر سزاے موت دینے کے بجائے ایسی تعزیری سزا پر اکتفا کیا جائے جو مجرم کو آئندہ اس جرم کے ارتکاب سے روکنے میں موثر ہو۔
اپنے تبصرے میں، میں نے عمار خان صاحب کے نقلی وعقلی استدلال کا رد کیا اور واضح کیا کہ گستاخ ذمی کے بارے میں فقہاے احناف کا موقف بیان کرنے میں علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت سے مغالطہ لگا ہے اور یہ کہ فقہاے احناف کا وہ موقف نہیں ہے جو عمار خان صاحب نے سمجھا ہے، بلکہ حنفیہ میں سے امام محمد رحمہ اللہ اور متاخرین کا موقف یہ ہے کہ ذمی اگر توہین رسالت کرے تو اس کی سزاے موت دو میں سے صرف ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی توہین یا تو اعلانیہ کی ہو یا خفیہ کی ہو تو وہ ایک دفعہ کے تکرار کے ساتھ پھر ہو۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی دوسرے مقام پر بعض عبارات سے بھی ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً رد المحتار میں ہے:
قولہ (وسب النبی) ای اذا لم یعلن فلو اعلن بشتمہ او اعتادہ قتل ولو امراۃ وبہ یفتی (ج ۶ ص ۳۳۴)
قولہ (وبہ افتی شیخنا) ای بالقتل تعزیرا کما قدمناہ عنہ وینبغی تقییدہ بما اذا ظہر انہ معتادہ کما قیدہ بہ فی المعروضات او بما اذا اعلن بہ کما یاتی (ج ۶ ص ۳۳۴، طبع دار المعرفہ بیروت)
اپنے تبصرے کے شروع ہی میں، میں نے واضح کر دیا تھا کہ :
’’ذمی یعنی مسلمان ملک کا کافر شہری اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عمار خان صاحب نے اسی سے متعلق یہ کتاب لکھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان توہین رسالت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال سے متعلق انھوں نے اس کتاب میں کوئی بحث نہیں کی۔‘‘
حاصل یہ ہے کہ عمار خان صاحب نے ذمی کے توہین رسالت کرنے پر اپنی کتاب لکھ کر شائع کی اور میرا تبصرہ اسی کتاب پر تھا، اس لیے میرا تبصرہ بھی ذمی سے متعلق ہے۔ مسلمان توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اس میں مجھے علامہ شامی رحمہ اللہ کے موقف سے اتفاق ہے، لیکن مسلمان کے مسئلہ سے نہ تو عمار خان صاحب نے تعرض کیا ہے اور نہ ہی میں نے کیا ہے، لیکن جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب، آپ نے اکتوبر ۲۰۱۱ء کے الشریعہ میں جو اپنی چند گزارشات لکھی ہیں، وہ صرف اور صرف توہین رسالت کرنے والے مسلمان سے متعلق ہیں۔ مثلاً آپ نے لکھا ہے:
’’پہلی گزارش یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے لعین شاتم رسول کے لیے توبہ کی گنجائش کے مسئلہ پر علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اب سے پونے دو سو برس قبل خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ موقف اختیار کیا تھا....‘‘ الخ
پھر مسلمان شاتم ہی کے بارے میں آپ نے تائید کے طور پر لکھا:
’’۱۔ امام ابویوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج ص ۱۸۲ میں لکھا ہے کہ جو مسلمان جناب رسول اکرم کی شان اقدس میں گستاخی کرے ..... ۲۔ اسی طرح امام طحاوی نے بھی مختصر الطحاوی ص ۲۶۲ میں یہی موقف بیان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک ایسا شخص مرتد ہے..... الخ (اور مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو۔ عبدالواحد) ۳۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد ج ۵ ص ۶۰ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: ایما مسلم سب اللہ و رسولہ .... (یعنی جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو سب وشتم کرے۔‘‘
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنے مضمون ’’تنبیہ الولاۃ والحکام‘‘ میں مسلمان شاتم رسول کے لیے علیحدہ فصل قائم کی ہے اور ذمی شاتم رسول کے لیے مستقل علیحدہ فصل قائم کی ہے۔
امید ہے کہ آپ اپنی گزارشات پر نظر ثانی کریں گے۔
نوٹ: آپ ہمارے قابل احترام بزرگ ہیں اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم دیکھو، دین کی بات کس سے لے رہے ہو۔ اسی طرح یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جو شخص نااہل ہو، خواہ وہ عام آدمی ہو یا پروفیسر ہو یا کم علم یا ناقص علم عالم ہو، وہ اگر قرآن پاک کے بارے میں کچھ کہے اور اتفاق سے وہ بات درست ہو، تب بھی اس نے غلطی کی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی اشکال پیش آتا ہے تو اس کا حل بتانا علماء سے مطلوب ہے۔ اس کے باوجود آپ شرعی احکام میں اور قرآن وحدیث کے بارے میں آزادانہ بحث ومباحثہ کے حق میں ہیں جس میں اس کی کوئی تمیز نہیں کہ رائے دینے والا واقعہ اہل ہے یا نہیں اور اس کا تو ہم آپ سے مطالبہ ہی نہیں کرتے کہ آپ بتائیں کہ اب تک الشریعہ کے آزاد بحث ومباحثہ سے کتنے لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے، کیونکہ جن کے سامنے یہی نہ ہو کہ حق کیا ہے اور حقانیت کیا کا کیا معیار ہے، وہ حق کو کیا سمجھیں گے۔ ہم آپ کی روش سے دل گرفتہ ہیں۔ کیا ہمارے لیے آپ کی طرف سے مایوسی اور حسرت وافسوس ہی مقدر ہے؟ والی اللہ المشتکی۔
[مولانا مفتی] عبد الواحد
دار الافتاء جامعہ مدنیہ، لاہور
20-10-2011
(۲)
محترمی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب زید مجدکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی؟
یاد فرمائی کا تہہ دل سے شکریہ!
- توہین رسالت کے مرتکب مسلمان اور ذمی کے مابین فرق کے ضمن میں آپ کی وضاحت مفید ہے اور اس سے قارئین کو آپ کا موقف سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ میں نے ذمی کی طرف سے توہین رسالت کے شرعی حکم پر اپنی گزارشات میں کچھ عرض نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مسئلہ کے مختلف پہلووں پر بحث نہیں کی، بلکہ اس پر اظہار خیال کرنے والے حضرات کے رویوں پر بات کی ہے جس پر مثال کے طو رپر میں نے مسئلہ کے صرف ایک پہلو کا ذکر کیا ہے اورمیرے خیال میں رویوں کو زیر بحث لانے کے لیے ایک مثال بھی کافی ہوتی ہے۔ میرا اصل موضوع مباحثہ میں حصہ لینے والوں کا طرز استدلال اور ان کے رویے ہیں جن پر میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور میں نے مجموعی طور پر جن تحفظات کا اظہار کیا ہے، ان پر کسی نظر ثانی کی ضرورت محسوس کیے بغیر اب بھی قائم ہوں۔ - عمار خان کی کتاب پر آپ نے جو تبصرہ فرمایا ہے، آپ نے اپنے نقطہ نظر کے اظہار کا جائز حق استعمال کیا ہے جس پر مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ میں نے اس مضمون میں آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے قبل ایک عریضہ میں عمار خان کے مضامین پر علمی نقد کے حوالے سے آپ کا الگ طور پر بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ بزرگانہ شفقت آئندہ بھی قائم رہے۔
- جہاں تک علمی واجتہادی مسائل پر کھلے مباحثہ کے بارے میں ہمارے طرز عمل پر آپ کے تحفظات ہیں، میں اسے آپ کا حق سمجھتا ہوں، مگر عمومی مباحثہ کامطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص کو راے کا حق حاصل ہو۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی مسئلے پر کسی کو راے دینے سے روکا نہیں کیا گیا۔ ہاں، دلیل اور استدلال کی بنیاد پر کسی کی بات جمہور اہل علم کے ہاں قبولیت پا گئی ہے تو اسے علمی دنیا میں جگہ مل گئی ہے اور اگر جمہور اہل علم کے ہاں اسے قبولیت نہیں ملی تو وہ تاریخ کی نذر ہو گئی ہے۔ ہمارے علمی اور فقہی ذخیرے میں آ پ کو ہزاروں نہیں تو سیکڑوں ایسی آرا ضرور ملیں گی جن کا اظہار ہوا ہے اور وہ جمہور اہل علم میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں۔ میری طالب علمانہ راے میں کسی راے کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا دائرہ الگ ہے اور کسی کو راے کا حق دینے یا نہ دینے کا دائرہ اس سے مختلف ہے۔ دونوں دائروں میں اگر اہل علم بھی فرق نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
- کون راے دینے کا اہل ہے اور کون اس کا اہل نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیے اور نہ آپ کو اس پر اصرار کرنا چاہیے ۔مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ ہمارے دار الافتاء یہ منصب بھی سنبھال لیں کہ افراد کے بارے میں ڈگریاں جاری کرنا شروع کر دیں کہ کون راے کا اہل ہے اور کون نہیں۔
اصول کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ ہمارے اسلاف نے راے دینے کی اہلیت اور راے کو قبول کرنے کے معیارات واضح کر دیے ہیں۔ ان کی بنیاد پر کسی کی راے کو قبول کرنے اور کسی کی بات کو رد کر دینے کا اختیار اب تک عمومی علمی ماحول کے پاس رہا ہے۔ جو شخص عمومی علمی ودینی ماحول میں قابل قبول قرار پایا ہے، اسی کی اہلیت تسلیم کی گئی ہے اور جسے جمہور اہل علم نے نظر انداز کر دیا ہے، وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ ماضی میں آپ کو بیسیوں حضرات ایسے ملیں گے جن پر شدید نقد وجرح کی گئی ہے اور فتوے بھی صادر کیے گئے ہیں، مگر انھیں علمی مباحثہ کے میدان سے نکالا نہیں جا سکا، جبکہ ایسے حضرات بھی کم نہیں ہیں جن کا ذکر صرف تاریخ کے ایک دو صفحات تک محدود ہے۔
اس لیے میری درخواست ہے کہ کسی شخص کے یا کسی رائے کے قابل قبول ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جمہور اہل علم اور عمومی علمی ماحول کے پاس ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ان فیصلوں کا اصل فورم وہی ہے۔
میں ایک بار پھر آپ کی توجہ فرمائی پر شکر گزار ہوں، آئندہ بھی اس کی توقع رکھتا ہوں اور اگر وہ کھلے دل کے ساتھ ’’دل گرفتگی‘‘ کے بغیر ہو تو یقیناًزیادہ لطف دے گی۔ شکریہ
ابو عمار زاہد الراشدی
۲۱؍ اکتوبر ۲۰۱۱ء
الشریعہ اکادمی میں تعزیتی نشست
ادارہ
۱۵ اکتوبر کو الشریعہ اکادمی میں مولانا سید عبد المالک شاہؒ ، مولانا میاں عبدالرحمنؒ اور مولانا قاری خلیل احمد نعمانی ؒ کی وفات پر ایک تعزیتی نشست کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی نے کی اور اس سے مولانا مفتی محمد اویس، مولانا حافظ گلزار احمد آزاد، ڈاکٹر عبد الماجد حمید المشرقی اور الشریعہ اکادمی کے ڈائریکٹر مولانا زاہد الراشدی نے خطاب کیا، جبکہ شہر کے علماء کرام اور دینی مدارس کے اساتذہ وطلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی نے مرحومین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا سید عبد المالک شاہؒ ان مجاہد علما میں سے تھے جو معاشرہ میں حق کی آواز بلند کیے رکھتے ہیں اور اس کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب مرحوم نے تدریس وخطابت کے ساتھ ساتھ بھرپور جماعتی وتحریکی زندگی گزاری ہے اور وہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود قدس اللہ سرہ العزیز کے معتمد ساتھیوں میں سے تھے۔ انھوں نے دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں تعلیم حاصل کی اور ان کے سبق اور کمرے کے ساتھیوں میں مولانا فضل الرحمن اور مولانا عبد الحکیم اکبری بھی تھے۔
مفتی صاحب نے فرمایا کہ معاشرہ میں حق کی آواز بلند ہوتی رہے اور منکرات کے خلاف روک ٹوک کانظام قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی رکا رہتا ہے اور اگر باطل اور منکرات کا فروغ عام ہو اور کوئی روک ٹوک نہ ہو تو پوری قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے وہ علماء کرام قوم کے محسنین ہیں جو حق کے اظہار اور باطل کے خلاف احتجاج میں مصروف رہتے ہیں اور مولانا سید عبد المالک شاہؒ بھی ایسے ہی علماء کرام میں سے تھے۔
مولانا میاں عبد الرحمنؒ کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد ابراہیمؒ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے خصوصی مریدین میں سے تھے اور حق گو عالم دین تھے جن کے رعب ودبدبہ کی وجہ سے انھیں ڈنڈے والے مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مولانا میاں عبد الرحمنؒ اپنے والد گرامی کے صحیح جانشین تھے۔ دینی درد رکھنے والے حق گو عالم دین اور دینی تحریکات میں بھرپور حصہ لینے والے متحرک کارکن تھے۔
مفتی صاحب نے مولانا قاری خلیل احمد نعمانی مرحوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی آف ظاہر پیر ضلع رحیم یار خان کے فرزند تھے۔ ایک عرصہ سے گوجرانوالہ میں مقیم تھے اور جامعہ اسلامیہ میں تدریسی خدمات سرانجام دے رہے تھے کہ گزشتہ دنوں وہ اچانک بیمار ہوئے اور آناً فاناً دنیا سے رخصت ہو گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ ایک صالح اور مخلص عالم دین تھے اور اکابر علماء کرام کے ساتھ مسلسل تعلق اور عقیدت رکھتے تھے۔
مولانا حافظ گلزار احمد آزاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا سید عبد المالک شاہؒ کے ساتھ ان کی تحریکی اور مسلکی رفاقت رہی ہے۔ وہ مسلکی کاموں میں ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ تعاون کرتے تھے اور دینی ومسلکی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ چھوٹے موٹے خلا تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن مولانا سید عبد المالک شاہؒ کی وفات پر شہر میں دینی جدوجہد اور مسلکی خدمات کے حوالے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اسے ان کے ساتھی کافی عرصے تک محسوس کرتے رہیں گے۔
مولانا مفتی محمد اویس نے اپنے خطاب میں ایک واقعہ سنایا اورکہا کہ اس واقعہ کے بعد ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مولانا سید عبد المالک شاہؒ کتنے بڑے بزرگ تھے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ ایک بار گوجرانوالہ کے تبلیغی مرکز میں امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری پر انھیں گکھڑ واپس چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ شیرانوالہ باغ کے قریب ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے گاڑی آہستہ ہو گئی۔ اتنے میں سامنے دیکھا کہ مولانا سید عبد المالک شاہؒ آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی رکوائی اور گاڑی سے اتر کر سڑک پر شاہ صاحبؒ سے ملاقات کی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ شاہ صاحبؒ کے علم، خلوص اور سید ہونے کی وجہ سے حضرت شیخؒ نے ان کا یہ اکرام فرمایا ہے اور شاہ صاحبؒ ہمارے بزرگوں کے معتمد ساتھیوں میں سے ہیں۔
پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد حمید المشرقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انھیں شاہ صاحبؒ کی جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ ان کی سادگی اور تواضع تھی۔وہ ہمارے پاس المشرق سائنس کالج میں کئی بار تشریف لائے۔ ان کی بچیاں ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتی تھیں، لیکن وہ جب بھی آئے، سادگی اور تواضع کے ساتھ بات کی اور کبھی اپنے علم اور بزرگی کا رعب جمانے کی کوشش نہیں کی اور میں ان کے اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوا کہ اہل حق اور بزرگوں کا طرز عمل ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔
ڈاکٹر عبد الماجد نے اس موقع پر ایک تجویز پیش کی کہ کچھ اصحاب خیر کو آپس میں مل کر کوئی ایسا مستقل فنڈ قائم کرنا چاہیے جس سے وفات پا جانے والے علماء کرام کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ انھوں نے کہا کہ وہ یہ تجویز ایک تلخ تجربہ کے بعد پیش کر رہے ہیں کہ ایک عالم کسی دینی جدوجہد میں گرفتار ہو گئے اور کئی ماہ تک جیل میں رہے۔ میں نے ان کی مسجد کی انتظامیہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ لوگ مولانا صاحب کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ان کو کوئی خرچہ دے رہے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے گھر میں کوئی خرچہ نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ مسجد کی تو کوئی ڈیوٹی نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر مشرقی نے کہا کہ ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم دین کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے یا وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے خاندان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس لیے میری تجویز ہے کہ ایسا کوئی فنڈ مستقل طور پر قائم ہونا چاہیے۔
مولانا زاہد الراشدی نے اپنی گفتگو میں مولانا سید عبد المالک شاہ، میاں عبدالرحمن اور قاری خلیل احمد نعمانی کی دینی خدمات کا مختصر تذکرہ کیا۔ انھوں نے بتایا کہ ملکی حالات کے بارے میں مولانا سید عبدالمالک شاہ کی فکر مندی کا حال یہ تھا کہ بیماری کے دنوں میں، جبکہ شوگر کی وجہ سے ان کا ایک پاؤں کاٹا جا چکا تھا، میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں ان سے ان کی طبیعت کے متعلق پوچھتا اور وہ مجھ سے مختلف قومی اور ملی مسائل سے متعلق دریافت کرتے رہے۔ انھوں نے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے بتایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شدید علالت کی اس کیفیت میں شاہ صاحب جمعیت کی کسی میٹنگ میں شریک ہوں گے، لیکن وہ ہر میٹنگ میں سب سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں ایسے دوستوں کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبد الماجد المشرقی کی تجویز پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔
تقریب کا اختتام مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی کی پرسوز دعا پر ہوا اور تینوں مرحومین کی مغفرت وبلندئ درجات کے ساتھ ساتھ ان کے پس ماندگان ومتوسلین کے لیے صبر جمیل کی توفیق کی دعا کی گئی۔ اللہم آمین
اگر جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے!
حکیم محمد عمران مغل
دیگر ملکوں کی طرح ہمارے ملک کے بڑے شہر بھی حادثات کی زد میں آ چکے ہیں۔ لڑائی مار کٹائی، دنگا فساد اور کسی اونچی جگہ سے گرنے کے علاوہ ٹریفک کے حادثات بھی بے تحاشا بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو آبادی اور ٹریفک دونوں بے ہنگم ہو چکے ہیں جس سے عام آدمی کا بازاروں میں حفاظت سے چلنا دشوار ہو چکا ہے۔ کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں حادثہ پیش آ ہی جاتا ہے۔ پھر ہماری مصروفیات اور دوڑ دھوپ میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ ہر شخص، کیا مرد کیا عورت، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کی راہ پر گامزن ہے۔ کراچی کی طرح لاہور میں بھی آبادی کا دریا چاروں طرف بہہ نکلا ہے جو سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔
گئے وقتوں میں اچھرہ، لاہور کا ایک پرسکون، مہذب اور دل آویز گاؤں ہوتا تھا۔ اسی نسبت سے لاہور کے ماتھے پر علم وادب کا ایک لازوال جھومر لٹکایا گیا جس کی چمک برصغیر سے نکل کر عرب وعجم تک پہنچی۔ یوں علم کے متوالے یہاں کھنچے چلے آئے۔ یہ جھومر جامعہ فتحیہ المعروف جٹاں والی مسجد کے نام سے آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ جب لاہور کے دینی مدارس کا ذکر آتا ہے تو جٹاں والی مسجد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی شہرت کو سن کر سوات کے ایک دینی گھرانے کا طالب علم جنید یہاں آیا۔ فارغ ہونے کے بعد وہ مدرس سے ناظم بن گیا اور اپنی محنت سے جامعہ فتحیہ کو چار چاند لگا دیے۔ ایک دن وہ سائیکل پر سوار فیروز پور روڈ پر پہنچا تو مخالف سمت سے ایک گاڑی دھاڑتی ہوئی آئی اور آناً فاناً اسے کچل کر رکھ دیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ
دنیا ہے چل چلاؤ کا رستہ سنبھل کے چل
بے چارے جنید کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ مالکان مدرسہ نے اس کا قیمتی سے قیمتی علاج کروانے کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دیے، مگر افاقہ نہ ہوا اور چارپائی پر پڑے کراہتے رہنا اس کا مقدر دکھائی دینے لگا۔ جب مجھے معائنہ کے لیے بلایا گیا تو سارے جسم میں پیپ پڑ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ علاج کے ساتھ سخت پرہیز نہ کیا گیا تو صورت حال بگڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلے پیپ کو خشک کرنے کے لیے رسکپور مدبر ایک چاول کے برابر کیپسول میں ڈال کر ناشتے کے بعد دودھ سے دیا۔ ساتھ چھ دیسی انڈوں کی زردی سے تیل کشید کر کے اس میں میتھی اتنی رگڑی کہ مرہم بن گئی۔ اس مرہم کے ساتھ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر پٹی باندھی گئی۔ چار دن کے بعد نئی پٹی باندھی۔ ساتھ صبح شام ایک ایک چاول سلاجیت کھانے کے بعد دی جاتی رہی۔ مزید برآں معجون فلاسفہ بڑی چمچ دوبار، صبح شام حب ازاراقی، کیلشیم کی کمی کے لیے خمیرہ مروارید صبح شام دیا جاتا رہا۔ دو ماہ کے علاج کے بعد جنید صاحب نے دیوار کے سہارے چلنا شروع کر دیا اور پھر چل سو چل۔
بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ اور جگرانوی خاندان نے علم نجوم سیکھنے کی بہت تاکید کی ہے۔ بو علی سینا تو فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے علم نجوم نہیں سیکھا، مکمل حکیم نہیں بن سکا۔ آج ہمارے ہاں حکیموں کے لیے اردو زبان میں معمولی مضمون لکھنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ان بزرگوں نے حکیم کے لیے علم نجوم، علم جفر، پامسٹری، علم قیافہ اور علم نقوش کا جاننا ضروری قرار دیا ہے۔ یہ سارے نکات کاش البرنی نے وضاحت سے سمجھائے ہیں۔ ان کو ہم تک پہنچانے میں کاش البرنی خاندان نے کافی تکالیف اٹھائی ہیں۔ اس لیے میں نے ان کو شہید علم لکھا ہے۔ ان علوم کے بازاری حاملین نے آج اودھم مچا رکھا ہے۔ اگر کاش البرنی کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے تو برنی صاحب کی شخصیت کا نکھار کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔
دسمبر ۲۰۱۱ء
آزادانہ بحث و مباحثہ اور ’الشریعہ‘ کی پالیسی
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
محترم ڈاکٹر محمد امین صاحب ہمارے قابل احترام دوست ہیں، تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے ایک عرصے سے سرگرم عمل ہیں، ’’ملی مجلس شرعی‘‘ کی تشکیل میں ان کا اہم کردار ہے اور دینی حمیت کو بیدار رکھنے کے لیے مسلسل تگ ودو کرتے رہتے ہیں۔ انھوں نے اپنے موقر جریدہ ’’البرہان‘‘ کا اکتوبر ۲۰۱۱ء کا شمارہ جناب جاوید احمد غامدی کے افکار وخیالات پر نقد وجرح کے لیے مخصوص کیا ہے اور اس ضمن میں راقم الحروف، ماہنامہ ’الشریعہ‘ اور عزیزم عمار خان ناصر سلمہ پر بھی کرم فرمائی کی ہے جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔
ڈاکٹر صاحب محترم کے دینی معاملات میں عزم وجذبہ کا میں پہلے سے ہی معترف ہوں، مگر اب ان کی ایک اور صلاحیت سے آگاہی حاصل کر کے بہرحال مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ایک اچھے ’’مناظر‘‘ بھی ہیں اور مناظرانہ داؤ پیچ استعمال کرنے پر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ انھیں شکوہ ہے کہ:
- ’الشریعہ‘ غامدی صاحب کے افکار کی اشاعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔
- ’الشریعہ‘ کی آزادانہ مکالمہ اور بحث ومباحثہ کی پالیسی ان کے خیال میں ضرورت سے زیادہ ’آزادانہ‘ ہے۔
- جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں راقم الحروف کا موقف واضح نہیں ہے۔
- میرا بیٹا اور ’الشریعہ‘ کا مدیر حافظ محمد عمار خان ناصر سلمہ جاوید غامدی صاحب کے افکار کا مبلغ ہے اور اس کے باوجود میں نے اسے ’الشریعہ‘ کے مدیر کے طور پر برقرار رکھا ہوا ہے۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کے ان شکووں کا تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے کہ شکوہ کرنا ان کا حق ہے اور اس پر اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ’الشریعہ‘ جناب جاوید احمد غامدی کے افکار کی اشاعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ بات خلاف واقعہ ہے، اس لیے کہ ’الشریعہ‘ کی فائل گواہ ہے کہ اس میں غامدی صاحب کے افکار پر تنقید کے حوالے سے بھی بیسیوں مضامین شائع ہوئے ہیں جن میں سے کم وبیش ایک درجن مضامین خود میرے ہیں جن میں غامدی صاحب کے افکار کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور ان پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ قارئین گزشتہ چند سالوں کی فائل پر ایک نظر ڈال کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب کے افکار کے حوالے سے ’الشریعہ‘ میں بحث ومباحثہ کا آغاز بنیادی طور پر ان کے افکار پر تنقیدی مضامین سے ہوا ہے جبکہ غامدی صاحب کے حلقہ فکر کی طرف سے موصول ہونے والے مضامین محض جوابی طو رپر ’الشریعہ‘ کی اس پالیسی کے تحت شائع کیے گئے ہیں کہ مباحثہ کے دونوں فریقوں کو اپنا موقف اور استدلال واضح کرنے کا حق حاصل ہے اور قارئین تک دونوں اطراف کا نقطہ نظر براہ راست پہنچنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی موقف کے وزنی یا کمزور ہونے کا فیصلہ خود کر سکیں۔
ڈاکٹر صاحب محترم کو ’الشریعہ‘ میں آزادانہ مباحثہ کی پالیسی پر شکوہ ہے اور وہ اسے آزادی کے مغربی فکر کے مترادف قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ’الشریعہ‘ کی پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے ’البرہان‘ کے اسی شمارے میں وہ خود راقم الحروف کی یہ گزارش نقل کر چکے ہیں کہ:
’’راقم الحروف کے نزدیک اسلامی قوانین واحکام کی تعبیر وتشریح کے لیے صحیح، قابل عمل اور متوازن راستہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اجماعی تعامل اور اہل السنۃ والجماعۃ کے علمی مسلمات کے دائرہ کی، بہرحال پابندی کی جائے۔‘‘
’’مجھے ان نوجوان اہل علم سے ہمدردی ہے، میں ان کے دکھ اور مشکلات کو سمجھتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ امت کے اجماعی تعامل اور اہل السنۃ والجماعۃ کے علمی مسلمات کا دائرہ کراس نہ ہو، کیونکہ اس دائرے سے آگے بہرحال گمراہی کی سلطنت شروع ہو جاتی ہے۔‘‘
میں فی الواقع یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ راقم الحروف کی یہ گزارش نقل کرنے کے بعد بھی اگر ڈاکٹر صاحب موصوف کو ’الشریعہ‘ کی آزادانہ مباحثہ کی پالیسی پر اعتراض ہے تو ان کے اس اعتراض اور اس تجمد کے درمیان کیا فرق باقی رہ جاتا ہے جس کا رونا خود ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون میں پورے خلوص کے ساتھ رویا ہے۔
محترم ڈاکٹر محمد امین صاحب کی ایک شکایت یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں راقم الحروف کا موقف پوری طرح واضح نہیں ہے، جبکہ میں اس پر خود ان سے اس شکوے کا حق رکھتا ہوں کہ انھوں نے یہ رائے غامدی صاحب کے بارے میں میرے مضامین پڑھے بغیر قائم کر لی ہے، حتیٰ کہ ’’جناب جاوید احمد غامدی کے حلقہ فکر کے ساتھ ایک علمی وفکری مکالمہ‘‘ کے عنوان سے الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب میں انھیں صرف دو مختصر عبارتیں دکھائی دی ہیں جن کا انھوں نے اپنے مضامین میں حوالہ دیا ہے، مگر ان گیارہ مضامین کو دیکھنے کا انھیں موقع نہیں مل سکا جو ستر سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں اور جن میں غامدی صاحب کے افکار وخیالات پر علمی نقد کیا گیا ہے، جبکہ ان کے بارے میں محترم نعیم صدیقی صاحب مرحوم کا تبصرہ بھی ان کے مکتوب گرامی کی صورت میں اسی کتاب میں موجود ہے جس میں انھوں نے فرمایا ہے کہ:
’’میں نے آپ کی جرات مندی کو سراہا کہ اکیلے میدان میں اترے اور دوسری طرف سے تین چار نوجوانوں کا جتھا آپ کے پیچھے لگ گیا، مگر کہیں خم آپ نے بھی نہیں کھایا۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں آپ کی مدد کو نکلوں، مگر کم علم الگ، میری صحت کی کشتی گرداب میں ہے۔‘‘
ڈاکٹر محمد امین صاحب میرے قابل صد احترام بھائی، دوست اور دینی معاملات میں رفیق کار ہیں۔ مجھے ان سے اس یک طرفہ طرز عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی، اس لیے میں اس حوالے سے مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے انھیں مشورہ دوں گاکہ وہ ’الشریعہ‘ میں غامدی صاحب کے حوالے سے شائع ہونے والے میرے مضامین کا، جو ’’ایک علمی وفکری مکالمہ‘‘ میں موجود ہیں، ایک بار پورا مطالعہ کر لیں۔ اس کے بعد غامدی صاحب کے بارے میں میرے موقف کی مزید وضاحت کا تقاضا کریں۔ البتہ اس کتاب پر اپنے ہی تحریر کردہ پیش لفظ کا ایک اقتباس سردست نقل کر رہا ہوں:
’’غامدی صاحب نے جس انداز سے دین کی بنیادی اصطلاحات کی تشکیل نو کی ہے اور اصطلاحات کے الفاظ کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے مفہوم ومصداق کے حوالے سے جو نیا تانا بانا بنا ہے، وہ اجتہاد اور تجدید کے قدیمی اور روایتی مفہوم کے بجائے تشکیل نو (Reconstruction) کے دائرے میں آتا ہے۔ ہمارا ان سے اصولی اختلاف یہی ہے اور ہم پورے شرح صدر اور دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی دین کے پورے ڈھانچے کی تشکیل نو کی بات ہوگی، دین کی بنیادی اصطلاحات کو نئے معانی دے کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور امت کے چودہ سو سالہ علمی ماضی کے خلاف بے اعتمادی کی فضا پیدا کر کے نئی نسل کو اس سے کاٹنے کی سوچ کارفرما ہوگی، وہاں ایسی کوششوں کا عملی نتیجہ گمراہی کا ماحول پیدا کرنے کے سوا کچھ برآمد نہیں ہوگا۔‘‘ (ایک علمی وفکری مکالمہ، ص ۸)
اس وضاحت کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کی نشان دہی فرمائیں، اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ ہاں، اپنی چند ’’کمزوریوں‘‘ کا اس موقع پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کا لحاظ ضرور رکھا جانا چاہیے۔
ایک یہ کہ ’’لٹھ مار تنقید‘‘ کا نہ میرے اندر سلیقہ موجود ہے اور نہ ہی اس کا عادی ہوں۔ کوئی دوست طبع آزمائی کریں تو برداشت کسی نہ کسی طرح کر لیتا ہوں، مگر خود ایسا کرنے کا سرے سے مجھ میں حوصلہ ہی نہیں ہے۔ سادہ لہجے میں اور حتی الوسع طالب علمانہ انداز میں رائے سے اختلاف کرتا ہوں اور ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ بات علمی دائرے سے باہر نہ نکلنے پائے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے اسی ذوق کی تربیت پائی ہے۔
دوسری کمزوری جس کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں، مجھ میں یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی نیتوں اور دلوں کا حال جان سکوں۔ ظاہر کا مکلف ہوں اور اسی دائرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں، البتہ کسی صاحب کی رائے اور موقف کے ممکنہ نتائج وثمرات کے حوالے سے بات ضرور کر لیتا ہوں، جیسا کہ میں نے غامدی صاحب کے بارے میں بھی سطور بالا میں عرض کیا ہے، مگر نیت اور دل تک مجھے رسائی حاصل نہیں ہے کہ کسی کو حتمی لہجے میں کسی کا ایجنٹ قرار دے سکوں۔
چند سال پہلے اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک سیمینار میں ملک کے ایک بڑے دانش ور نے چند معاشی مسائل کے بارے میں ایک صاحب علم کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انھوں نے سرمایہ داروں کے کہنے پر یہ موقف اختیار کیا ہے۔ میں نے اسی اسٹیج پر اس بات سے کھلے بندوں اختلاف کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ بارے ہمارے کلچرل مزاج اور نفسیات کا حصہ بن چکی ہے کہ ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں، اسے کسی نہ کسی کا ایجنٹ قرار دیے بغیر ہماری نفسیات کی تسکین نہیں ہوتی۔ میں نے وہاں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اجتماعی معاملات میں جو بھی موقف اختیار کیا جائے گا، وہ معروضی حالات میں کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ دے گا، اس لیے یہ کہنا کہ وہ موقف کسی فریق سے پیسے کھا کر اپنایا گیا ہے، یک طرفہ نہیں رہے گا، دوسری طرف کے بارے میں بھی آسانی کے ساتھ یہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جناب جاوید احمد غامدی اور ان کی قسم کے دیگر اصحاب دانش پر نقد وتبصرہ کے حوالے سے خود ڈاکٹر محمد امین صاحب کا ایک ارشاد بھی یہاں نقل کرنا مناسب دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے ’البرہان‘ کے زیر نظر شمارہ کے ص ۵۸ پر فرمایا ہے کہ:
’’علماء کرام یہ بھی غور نہیں فرماتے ہیں کہ آج مغربی تہذیب اگر فاتح، غالب اور قوی ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مضبوط علمی وفکری بنیادوں پر کھڑی ہے، لہٰذا مسلم معاشرے کے لیے اس کا چیلنج حربی اور سیاسی ہی نہیں، علمی اور فکری بھی ہے، لیکن معاف کیجیے گا! علماء کرام اس کا جواب کیا دیں گے، وہ تو اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انھیں تو ’’مقاصد الفلاسفہ‘‘ کا ادراک نہیں، ’’تہافت الفلاسفہ‘‘ کا ادراک وہ کیسے کریں گے؟ محض یہ کہہ دینا کہ ہمارا موقف مبنی برحق ہے اور ان کا موقف غلط ہے، کافی نہیں جب تک ہم مروجہ علمی اسالیب میں اپنے موقف کا صحیح ہونا اور ان کے موقف کا خام، ناقص اور غلط ہونا دلائل کے ساتھ ثابت نہیں کر دیتے۔ اس کے مقابلہ میں جاوید غامدی صاحب اور ان کے ..... تلامذہ ذہین اور محنتی ہیں، وسیع المطالعہ ہیں، جدید تعلیم یافتہ ہیں، مغربی نفسیات کو سمجھتے ہیں، بات متانت، شائستگی اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں اور موثر انداز میں کرتے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب صحیح فریکونسی میں دیتے ہیں تو لوگ ان کی بات کیوں نہ سنیں اور ان سے متاثر کیوں نہ ہوں؟
علماء کرام غور فرمائیں کہ دینی مدارس، مساجد کے ائمہ وخطبا، ان کی دعوتی تنظیموں (تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی وغیرہ) اور اصلاحی اداروں (صوفیاء اور ان کی خانقاہوں) کو کیا مغربی فکر وتہذیب اور مسلم معاشرے میں اس کے تعامل واثرات سے پیدا ہونے والے مسائل اور چیلنجز کا ادراک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مغرب کے پیدا کردہ علوم اور فکر نے مسلم معاشرے کے لوگوں کا، جنھوں نے مغربی فکر پر مبنی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے، ایک خاص ذہن (mindset) بنایا ہے جس سے ہماری روایتی فکر نہ آگاہ ہے اور نہ اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس چیز نے ایک خلا پیدا کر دیا ہے۔ جاوید غامدی صاحب اور ان کے رفقاء کار اس خلا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے پر کر رہے ہیں، لہٰذا غامدی صاحب پر کفر اور گمراہی کے فتوے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک علماء کرام اس تجمد کے ماحول اور اپنی فرقہ واریت سے باہر نہیں نکلیں گے اور اپنے آپ کو عصر حاضر کے علمی وفکری چیلنج کا جواب دینے کا اہل نہیں بنائیں گے۔‘‘
ہم ڈاکٹر صاحب محترم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ہمارا موقف اور ’الشریعہ‘ کا مقدمہ ہم سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں اپنے مذکورہ ارشاد میں سمو دیا ہے۔ ہم شاید اتنے اچھے پیرایے میں اسے پیش نہ کر سکتے۔
عزیزم عمار خان ناصر سلمہ کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب موصوف نے تند وتیز شکوہ کیا ہے، مگر مجھے اس سے کلی اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے ہاتھوں میں پلا بڑھا ہے، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اپنے دادا محترم شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہے، اس نے جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں درس نظامی کی تعلیم کی تکمیل کی ہے اور دورۂ حدیث کیا ہے۔ اس کے بعد موقوف علیہ تک درس نظامی کی کتابیں دس گیارہ سال تک مسلسل پڑھائی ہیں۔ تدریسی اور کتابی ذوق رکھتا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی اور شغل نہیں ہے۔ غامدی صاحب سے اس کا تلمذ کا تعلق ہے اور ان کے بعض افکار سے وہ متاثر ہے، جبکہ کچھ عرصہ تک ان کے ادارے کے ساتھ بھی اس کا جزوی تعلق رہا ہے۔ اس کے بعض خیالات اور مضامین سے خود میں نے بھی اختلاف کیا ہے اور ’الشریعہ‘ کے صفحات پر کیا ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن کسی صاحب فکر کے بعض نتائج فکر سے ہم آہنگ ہونا اور بات ہے اور اس کی مکمل فکر کا مبلغ ہونا اور بات ہے۔ اس فرق کو اگر ڈاکٹر امین صاحب بھی نہیں سمجھ سکیں گے تو اور کون سمجھے گا؟
پھر بعض باتیں خواہ مخواہ ’’غامدیت‘‘ کے طعنے کی آڑ میں عمار خان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ مثلاً مسلمان شاتم رسول کے لیے توبہ کی گنجائش کے بارے میں احناف متقدمین کے موقف کی بات صرف عمار خان نے نہیں لکھی، بلکہ علامہ شامیؒ کا موقف بھی یہی ہے اور دور حاضر کے مفتیان کرام میں سے الشیخ عبد العزیز بن بازؒ اور ہمارے ہاں مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی، مولانا مفتی عبد الواحد اور مولانا مفتی محمد زاہد نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے اور خود میرا طالب علمانہ موقف بھی یہی ہے، حتیٰ کہ ممتاز اہل حدیث عالم دین مولانا حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی یہی لکھا ہے اور یہ سب کچھ ’الشریعہ‘ میں تفصیل کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ اب صرف اس وجہ سے کہ اس موقف کا حوالہ غامدی صاحب نے بھی دیا ہے، کھینچ تان کر اسے ’’غامدیت‘‘ قرار دینا او رپھر طعن وتشنیع کی توپوں کے دہانے کھول دینا نہ صرف یہ کہ علمی دیانت کے منافی ہے بلکہ ائمہ احناف کے علمی موقف کی اہانت واستخفاف بھی ہے جس سے ڈاکٹر امین صاحب جیسے صاحب دانش کو بہرحال گریز کرنا چاہیے تھا۔
اس موقع پر ان امور ومسائل پر بحث ومباحثہ کا مثبت ماحول پیدا کرنے اور علم وتحقیق سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے میں اپنا اصولی موقف ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں جس کا اظہار ایک سے زیادہ مواقع پر کر چکا ہوں اور ابھی ماہ اکتوبر ۲۰۱۱ء کے ’الشریعہ‘ میں ایک تفصیلی سوال نامہ کے جواب میں بھی وہ درج ذیل الفاظ میں موجود ہے:
’’آج کے حالات میں آزادانہ بحث و مباحثہ کے بغیر کسی بھی مسئلے میں منطقی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ اور تعلیمی مراکز نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مختلف اطراف سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو مہم شروع کر رکھی ہے، اس کے اثرات سے نئی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارا روایتی اسلوب کافی نہیں ہے۔ ماضی نے اپنا علمی خزانہ کتابوں اور سی ڈیز کی شکل میں اگل دیا ہے اور آج کوئی بھی ذی استعداد اور با صلاحیت نوجوان اپنے چودہ سو سالہ علمی ماضی کے کسی بھی حصہ کے بارے میں معلومات حاصل کر نا چاہے یا کسی بھی طبقے کا موقف اور دلائل معلوم کرنا چاہے تو اسے اس کے بھرپور مواقع اور وسائل ہر وقت میسر ہیں۔ اس ماحول میں یہ کوشش کرنا کہ نوجوان اہل علم صرف ہمارے مہیا کردہ علم اور معلومات پر قناعت کریں اور علم اور معلومات کے دیگر ذرائع سے آنکھیں اور کان بند کر لیں ، نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں بلکہ فطرت کے بھی منافی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ہماری ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بات ہمارے فرائض میں شامل ہو جاتی ہے کہ مطالعہ اور تحقیق کے اس سمندر سے نئی نسل کو روکنے کی بجائے خود بھی اس میں گھسیں اور ان متنوع اور مختلف الجہات ذرائع معلومات میں حق کی تلاش یا حق کے دائرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی راہ نمائی کریں۔ چنانچہ علم و فکر کی دنیا میں میرا ذوق روکنے یا باز رکھنے کا نہیں بلکہ سمجھانے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کا ہے۔ کسی دوست کو یہ طریقہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے بحث و مباحثہ ضروری ہے، مسائل کا تجزیہ و تنقیح اور دلائل کی روشنی میں ان کا خالص علمی انداز میں تلاش کرنا ضروری ہے۔ ایک عرصہ تک میرا بھی یہ ذوق اور ذہن رہا ہے کہ تحقیق کا دائرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم اپنے ذہن میں پہلے سے طے کر چکے ہیں، اسے کسی نہ کسی طرح ثابت کر دیا جائے۔ مگر رفتہ رفتہ یہ بات ذہن میں راسخ ہوتی گئی کہ خود اپنی بات کو دلائل اور حقائق کے معیار پر پرکھنا بھی تحقیق کا اہم ہدف ہوتا ہے ۔ بہت سے مسائل میں اکابر اہل علم کا رجوع الی الحق بالخصوص حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی طرف سے اس کا باقاعدہ اہتمام میرے ذوق میں اس تبدیلی کا باعث بنا۔ ‘‘
باقی رہی بات ’الشریعہ‘ کی ادارت کی تو میں خود ڈاکٹر صاحب موصوف سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ آزادانہ علمی مباحثہ کے لیے، جس کی اصولی طور پر ڈاکٹر صاحب بھی تائید فرما رہے ہیں، کسی ایسے شخص کی ادارت کی ضرورت ہے جو خود بھی علمی بحث ومباحثہ کا ذوق اور صلاحیت رکھتا ہو یا ڈاکٹر صاحب کے بقول کسی ’’تجمد کے خوگر‘‘ کو اس منصب پر بٹھا دیا جائے اور پھر ڈاکٹر صاحب محترم کو شکوہ کرنا پڑے کہ اسے تو ’’مقاصد الفلاسفہ‘‘ کا ادراک نہیں، وہ ’’تہافت الفلاسفہ‘‘ کا ادراک کیسے کرے گا؟
گزشتہ دنوں ایک محترم دوست میرے پاس تشریف لائے اور بڑے خلوص کے ساتھ فرمایا کہ ’’آپ نے عمار خان کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔‘‘ میں نے ان کی اس ہمدردی اور خیر خواہی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انھیں تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑ رکھا ہے، بلکہ جہاں ضرورت محسوس ہو، اسے سمجھاتا ہوں، اس کی راہ نمائی کرتا ہوں اور جو بات اس کی سمجھ میں آ جائے، وہ مانتا بھی ہے۔ اس کے مزاج میں تعنت اور ضد بالکل نہیں ہے، البتہ بات سمجھ کر مانتا ہے۔ بہت سے معاملات میں اس نے میرے سمجھانے پر رائے تبدیل کی ہے، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں نے اسے بالکل آزاد چھوڑ رکھا ہے، البتہ میں نے اسے اس گھنے جنگل میں تنہا اور بے سہارا بھی نہیں چھوڑ رکھا کہ جس کا جی چاہے، اس پر غرانے کی مشق شروع کر دے۔ اتنی بات کا ہمارے دوست خیال رکھ سکیں تو ان کی نوازش ہوگی۔
دنیائے اسلام پر استشرقی اثرات ۔ ایک جائزہ (۱)
ڈاکٹر محمد شہباز منج
یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مستشرقین نے بالعموم اسلام کا معروضی مطالعہ پیش نہیں کیا۔ وہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے اسلام کی غیر حقیقی اور مسخ شدہ تصویر پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ اسلام کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ ان کو کوئی غیر معمولی اور خاص وقعت کی چیز محسوس نہ ہو بلکہ اس کے برعکس انسانی ترقی و تمدن کی راہ میں مزاحم دکھائی دے۔ اس سلسلے میں وہ کئی جہتوں میں کام کرتے اور مختلف نتائج سامنے لاتے ہیں۔ عالم اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو ان کی کوشش کا اہم مقصودمسلمانوں کو اپنے دین سے متعلق متشکک و مترددبنانا، اسلامی اقدار وتہذیب کو مغربی اقدار وتہذیب کے مقابلے میں کم تر ثابت کرنا اورانہیں یہ باور کرانا ہے کہ وہ مغربی تہذیب واقدارسے بیگانہ اور روایتی اسلام سے، جس میں دقیانوسیت اوربہت سے نقائص ہیں، چمٹے رہ کردنیا میں ترقی و عروج حاصل نہیں کر سکتے۔ اس مقالہ میں ہمارے پیش نگاہ مذکورہ مقصد کے حوالے سے مستشرقین کی کاوشوں اوران کے نتائج کا مطالعہ ہے۔
استشراقی مساعی کی نو عیتیں
موضوع زیر بحث کے حوالے سے مستشرقین کی کوششیں کئی نوعیت کی ہیں۔ کبھی وہ اسلام سے متعلق ایسا مواد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اہل اسلام میں روایتی اسلامی عقائد وتصورات سے متعلق شکوک وشبہات اور بیزاری و نفرت پیدا کرے، کبھی وہ تجدد کی طرف بلاتے اور جدید تصورات ونظریات اپنانے کو مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کاذریعہ قرار دیتے ہیں اورکبھی اسلامی تہذیب و تاریخ کی تحقیر کرتے ہیں۔ سطور ذیل میں مستشرقین کی ان مساعی کو قدرے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔
اساسی اسلامی عقائد پر نقد
مستشرقین اسلام کے اساسی عقائدو تصورات کو جدید افکارو نظریات کے تناظر میں اس طرح سے ہدف تنقیدبناتے اور ایسے نتائج سامنے لاتے ہیں کہ سطحی دینی علم کے حامل مسلمان ان عقائد وتصورات سے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات اور تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہ وحی پر کلام کرتے ہوئے کبھی اسے عقل و تجربے کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔۱ کبھی اس کی محض اسی صورت کو قابل قبول گردانتے ہیں جس میں کوئی چیز عقل سے ماورا نہ ہو۔۲ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی تعبیر (نعوذ باللہ) مرگی کے دوروں سے کرتے ہیں۳ا ور کبھی اسے آپؐ کے زمانے کے حالات کے فطری ردعمل اورآپ کی داخلی کیفیت سے تعبیرکرتے ہوئے اس کے خارج سے نزول کی نفی کرتے ہیں۔۴ معجزات پر بحث کرتے ہوئے انہیں قدیم غیر متمدن قوموں کی جہالت ووہم پرستی اورلا علمی سے تعبیر کرتے،۵ انہیں خلاف قانون قدرت،۶ ناممکن الوقوع۷ اور سائنسی نقطہ نظر سے غلط بتاتے،۸ اور بائبل۹ اور قرآن ۱۰ میں معجزات کے مذکور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اسے حضورؐ کااپنا کلام کہتے،۱۱ قصص قرآنی کوبائبل کی روایات پر منحصر قرار دیتے،۱۲ قرآن کو حضورؐ کے الہامات کی حیثیت سے آپؐ کے ساتھیوں کے جمع کردہ ۱۳ نامکمل مواد۱۴ کا نام دیتے، ناسخ و منسوخ پر معترض ہوتے۱۵ اور اعجاز القرآن کا انکار کرتے ہیں۔۱۶
حدیث پر تنقید کرتے ہوئے ذخیرۂ احادیث کو جعلی وفرضی اورپیغمبر اسلام اور آپؐ کے عہد سے متعلق معلومات کا ناقابل اعتبار ماخذ قراردیتے ہیں۔۱۷ سیرت طیبہ پر لکھتے ہوئے حضورؐ کے اخلاق وکردارکو ہدف تنقید بناتے،۱۸ آپؐ کے پیغام کی بسرعت اشاعت اور آپؐ کی غیر معمولی کامیابیوں کو اللہ کی مدداورآپ کی حقانیت پر محمول کرنے کی بجائے وقت کا تقاضا اور حالات کی سازگاری کا نتیجہ قرار دیتے،۱۹ تعدد ازواج کے حوا لے سے آپؐ کی سیرتِ بے داغ پر دھبے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے۲۰ اور آپ پر تشدد پسندی اوردین اسلام کو بزور شمشیر قائم کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔۲۱ معاد اور جنت ودوزخ سے متعلق اسلامی تصورات کو یہودیت و عیسائیت وغیرہ مذاہب سے اخذ کر کے، بے آب و گیاہ اور بنجر زمین کے باسی عربوں کومتاثر کرنے کی غرض سے مادی و حسی صورتوں میں پیش کیے گئے تصورات قرار دیتے ہیں۔۲۲ جہاد کو عربوں کے ہاں مروج ڈاکہ زنی کے عمل کا تبدیل شدہ نام۲۳ اور اسلام کی ترقی اور اشاعت کو تلوارپر منحصر بتاتے ہیں۔۲۴ اسلامی قانونِ تعدد ازواج کو اسلام کی اختراع کہتے۲۵ اور اس سے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے اور افسانے تراشتے ہیں۔۲۶ اسلامی قانون کوغیر عقلی،قدیم عربی روایات پر مبنی اور جادوئی وافسانوی قرار دیتے۲۷ اور اسلامی سزاؤں کو غیر ضروری طور پر سخت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔۲۸ کتب مقدسہ کے نظریہ تخلیق انسانی کو مسترد کرتے ہوئے انسانی ارتقا کا ایسا تصور پیش کرتے ہیں جس میں کسی خدائی منصوبے کو کوئی دخل حاصل نہیں۔۲۹
دعوتِ تجدد و اصلاحِ مذہب
مستشرقین اہل اسلام کو تجدد و مغربیت اور اصلاحِ مذہب کی دعوت دیتے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فلاح وترقی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ وہ جدیدمغربی تہذیب اپنائیں اور اپنے مذہب کو نئے حالات کے مطابق ڈھالیں۔ ان کے نزدیک مسلم معاشروں میں اٹھنے والی ایسی تحریکیں اور اشخاص حوصلہ افزائی اور تعریف و ستائش کے مستحق ہیں جو اسلام کو دور جدیدکے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذکورہ استشراقی کاوش کی وضاحت کے لیے چند مستشرقین کے خیالات ملاحظہ ہوں:
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نئے زمانے کا ساتھ دینے کے لیے اسلام کو اپنی روح میں تبدیلی پیدا کرنا لازم ہے، Kenneth Cragg لکھتا ہے:
"The modern mind is right in its instinctive awareness that Islam must either baptize change into its spirit or renounce its own relevance to life. Since it cannot do the later, it must somehow do the former."(30)
Cragg محمد کامل حسین کواس بنا پرداد دیتا ہے کہ اس نے اس بات پر اصرار کیاکہ خود اسلام ہی سے اسلام کاغیر معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔۳۱ وہ ایک اور مقام پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان وقت کے مطابق اسلامی احکامات میں از خود تبدیلی کرتے رہے ہیں جس سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کوئی مستقل دین نہیں تو دوسری طرف یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلام کو ضرورت کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔۳۲
فلپ کے ہٹی کے مطابق تعدد ازواج، چوری، جوا اور شراب وغیرہ سے متعلق اسلامی قوانین اور سزائیں جدید اسلامی سوسائٹی میں قابلِ عمل نہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج مسلم معاشرے میں ان کو در خور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔وہ کہتا ہے:
"Modern Islamic society has practically outgrown the Koranic legislation."(33)
کینٹ ویل اسمتھ مصطفی کمال کی اصلاحات کی تحسین کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کوبھی ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ترکوں نے بجا طور پر محسوس کیا کہ اسلام اپنے وقت پر پروگریسو تھا` مگر اب نہیں۔ اب اسلام اور کسی بھی دوسرے مذہب کو زندہ رہنے کے لیے جدید تعلیم یافتہ انسان کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈھالے۔ سمتھ کے نزدیک ایسی اصلاحات کا مطلب عیسائی بننا نہیں بلکہ ماڈرن بننا ہے۔۳۴ سمتھ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کا حل سیکولر ازم کو بتاتا ہے۔ وہ کانگرسی مسلمانوں کی تعریف کرتا اور تخلیق پاکستان کو ایک برائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان جتنا زیادہ ’اسلامی‘ ہوگا، ہندوستانی مسلمان اتنے ہی زیادہ غیر محفوظ ہوتے جائیں گے ۔۳۵
S.D.Goiteinکا کہناہے کہ قرآن جدید سوسائٹی کی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔وہ اسلام کو یہودیت سے مستعاربتاتا اور عربوں کو مقامی زبانیں اپنانے کا مشورہ دیتا ہے۔۳۶
یہودی مستشرق Nadve Safran اسلام کو ناقابل عمل اور غیر حقیقی قرار دیتا ہے ۔وہ رشید رضا کی خلافت سے متعلق کتاب پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رشید رضاکو مسلمانوں کے سابقہ تجربات سے کچھ سبق نہ مل سکا۔۳۷ وہ مصری قومیت پسند سید لطفی سے اظہار ہمدردی کرتاہے جو تجدد کا بہت بڑا نقیب اور اسلام کی بجائے فرعونیوں کی تقلید پر ابھارنے اورمصر میں نئے معتقدات اختیار کرنے اور پرانے اسلامی تصورات کو چھوڑنے کی ضرورت پر زور دینے والا تھا۔۳۸
الغرض مستشرقین سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اہل اسلام کو اپنے مذہب کو گردشِ زمانہ کے مطابق بدلنے اورمغربی تہذیب اور افکار ونظریات اپنانے پر مائل کیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض یونیورسٹیوں کے ذمہ باقاعدہ طور پر ایسے اسلامسٹ تیار کرنے کا کام لگایا گیا ہے جو اسلام سے متعلق جدید افکارکے حوالے سے سمجھوتے کی فضا پیدا کریں۔ ۳۹
اسلامی تاریخ و تہذیب کی تحقیر
مستشرقین اسلامی تاریخ و تہذیب سے متعلق متعصبانہ ۴۰ انداز نظر اختیار کرتے ہوئے ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے اور ان کی تحقیر کرتے ہیں۔وہ اسلامی تاریخی واقعات کی خلافِ حقیقت توجیہات پیش کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا ظہور وفروغ عالمِ انسانیت اور بالخصوص عیسائیت کے لیے فالِ بد ثابت ہوا۔ اسلام شروع ہی سے یہودیوں اور عیسائیوں کا دشمن بن گیااور مسلمانوں نے ہمیشہ جارحیت کا ارتکاب کیا۔ مثلاً Thomas Wright ابرہہ کے حملے کے دو ماہ بعد حضور ؐ کی پیدائش کو عیسائیوں کے لیے بد ترین آفت قرار دیتے ہوئے آپؐ کو مسیحیوں کا سب سے بڑا دشمن گردانتا ہے۔۴۱ فلپ کے ہٹی الزام لگاتا ہے کہ حضورؐ نے موتہ کی جنگ شروع کر کے اسلام اور عیسائیت میں طویل جنگ کی بنیاد رکھی۔۴۲ اسلامی تہذیب کی قدرو منزلت کوگھٹانے اور اس کی تحقیر کرنے اور عرب مسلمانوں کے تمدنی محاسن کے استخفاف کی خاطر مستشرقین اپنے طلبہ کو تربیت دیتے ہیں کہ وہ تہذیبی و ثقافتی مظاہر کو عربی الاصل ثابت کرنے کی بجائے لا طینی الاصل ثابت کریں تا کہ علم و فکر کے رشتے اور عقیدت و محبت کے جذبات مسلمانوں سے کٹ کر قدیم لاطینی اور یونانی اقوام کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔۴۳ وہ اسلامی تہذیب اپنانے والوں کو تو رجعت پسندی اور دقیانوسیت کے طعنے دیتے ہیں، لیکن اس کے بر عکس اسلامی تہذیب سے قدیم تر تہاذیب، جو زندگی کی صلاحیت اور ہرطرح کی افادیت سے محروم اور سینکڑوں ہزاروں برس سے ماضی کے ملبے تلے دبی ہیں، کے احیا کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کوقرآن اور اسلامی علمی ذخیرے سے لا تعلق بنانے کے لیے نئے زمانے کے تقاضوں کا واسطہ دے کر قرآنی عربی زبان اور عربی رسم الخط کی بجائے مقامی زبانوں اور لاطینی رسم الخط اپنانے پر مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔۴۴
عالم اسلام میں استشراقی اثر ونفوذ
مستشرقین کواپنی متذکرہ صدر مساعی سے جو مقاصد مطلوب تھے، ان میں وہ خاصی حد تک کامیاب رہے۔عالم اسلام میں اصلاح وترقی کے نام پرتجدد و مغربیت کے جتنے علمبردار پیدا ہوئے، ان کے افکار و نظریات پر استشراقی چھاپ واضح دکھائی دیتی ہے۔ مسلم دنیا میں اہل اقتدار اور طبقہ امرا کے علاوہ مسلم سکالرز اور دانشوروں کی بھی ایک بڑی تعداد مستشرقین سے متاثر ہے۔ سطور ذیل میں مذکورہ طبقوں میں استشراقی اثر ونفوذکا مطالعہ مختلف عنوانات کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔
اہل اقتدار اور طبقۂ امرا
عالم اسلام میں جہاں تک اہل اقتدار اور طبقہ امرا کا تعلق ہے، یہ بالعموم مغرب کے زیر اثر ہے ۔یہ لوگ بقول مریم جمیلہ اکثر وبیشتر اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اصلی اسلام کی بجائے مستشرقین اور عیسائی مشنریوں کا لندن اور امریکہ میں تیار کردہ اسلام کا ایک جدید، لبرل اور ترقی پسند ایڈیشن پیش کیا جائے۔۴۵ مسلم معاشروں میں مغربی طرز پر اصلاح و ترقی کے خواہاں زعما اور حکمرانوں نے اپنے معاشروں کو مغربی رنگ میں رنگنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے ۔ ترکی کے قوم پرست لیڈر ضیا گوک الپ پر مغربی اور ملحدانہ اثرات اتنے گہرے تھے کہ وہ کسی بھی قسم کی اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے یورپ کی مکمل نقل کا خواہاں تھا ۔ اس نے عالمگیراخوتِ اسلامی کے تصور کو مغربی تصورِ قومیت سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔وہ کہا کرتا تھا کہ ترکوں کو اپنی سر زمین کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے ۔ ان کے لیے حب الوطنی سے بڑھ کر کوئی اخلاقیات نہیں۔ ۴۶ مصطفی کمال اتاترک ،جو عالمِ اسلام کے طبقہ امرا وزعما میں بالعموم ایک آئیڈیل باور کیا گیا ہے، ترکی میں تجدد ومغربیت کا سب سے بڑا نقیب تھا ۔ اس نے حصول اقتدار کے بعد اسلام کو ترکوں کی عملی زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس کے خیال میں ترکی کی ترقی اس وقت ممکن نہ تھی جب تک اسلام کے اثرو نفوذ کو بالکل ختم نہ کر دیا جاتا۔ اس کے خیالات میں اسلام سے متعلق نفرت وحقارت بہت نمایاں ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے:
''Islam- This theology of an immoral Arab is a dead thing. Possibly it might have been suitable to the tribes in the desert. It is no good for a modern, progressive state. God's revelation! There is no God! There are only the chains by which the priests and bad rulers bound the people down."(47)
چنانچہ مصطفی کمال نے ترکی کو خدا کی بجائے مغربی تہذیب کی شکل میں ایک دیوتا عطا کیا۔ اس دیوتا کا وہ خود بھی وفادار حواری اور پر جوش پجاری تھا۔وہ مغربی تہذیب کو ملک کے چپے چپے میں رائج دیکھنے کا تمنائی تھا۔اس تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں چمک اور اس کے چہرے کی طمانیت دیدنی ہوتی۔۴۸ وہ کہا کرتا کہ عالم اسلام کی کم نصیبی اور پس ماندگی کی اصل وجہ خود کو نئی، روشن اور بلند پایہ مغربی تہذیب میں فٹ نہ کر سکنا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو اسی باعث کہ اب ہماری ذہنیت بدل رہی ہے۔۴۹ لہٰذا اس نے ترکی کو سیکولر سٹیٹ قرار دے دیا۔ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ قرار پایا۔خلافت کا ادارہ ختم کر دیا گیا۔ شرعی اداروں اور محکموں اور اسلامی شریعت کو ملک سے بے دخل کرکے مغربی قوانین نافذ کر دیے گئے۔ہر وہ چیز جس کا کوئی تعلق اسلام سے بنتا تھا، حرف غلط کی طرح مٹا ڈالی گئی۔عربی کی جگہ لاطینی رسم الخط جاری کر دیا گیا۔ اور تو اور عربی میں اذان تک ممنوع قرار پاگئی۔ مختصر یہ کہ ترکی قوم اور حکومت کی دینی اساس کو تھوڑ پھوڑ کر ختم کر دیا گیا اور قوم کا نقطہ نظر یکسربدل ڈالا گیا۔۵۰
استشراقی فکر نے صرف ضیا گوک الپ اور مصطفی کمال یا دیگر ترک زعما ہی کو اپنی گرفت میں نہیں لیا بلکہ اس کے اثرات تقریباً عالم اسلام کے تمام اعلیٰ تعلیم یافتہ،مقتدر اور صاحب اختیار طبقہ تک ممتد دکھائی دیتے ہیں۔ عالم اسلام میں جہاں بھی کوئی ملکی تعمیر وترقی کے لیے اٹھتا ہے،بالعموم تجدد ومغربیت اور کمالی طرز کی اصلاحات ہی کومقصود و منتہاسمجھتا ہے۔ ۱۹۵۲ء کامصری انقلاب اپنی بنیادوں میں مغربی زاویہ نگاہ لیے ہوئے آیا۔ اس کامقصد جمال عبد الناصر کے خیال میں یہ تھا کہ مصری عربی معاشرہ ایک ایسی سوسائٹی میں بدل جائے جس کے افراد اپنے اجتماعی تعلقات،اخلاقی قدروں اور حقوق وغیرہ سے متعلق ایسا نقطہ نظر اختیار کریں جو جدید فکر سے ہم آہنگ ہو۔ صدرناصر کے پیش کردہ منشور سے اگر مصر اور عرب لفظ نکال دیں تو وہ کسی بھی سیکولر سوشلسٹ سٹیٹ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ رضا شاہ پہلوی نے اپنے زمانے میں ایران کو بھی ترکی کے نقش قدم پر مغربیت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں کیں۔وہ ایران سے مذہبی رجحان کوپوری طرح مٹانا اور اسلامی تشخص کو ختم کرنا چاہتا تھا، تاہم اس کی متشددانہ پالیسیاں۱۹۷۴ء کے شیعی اسلامی انقلاب پر منتج ہوئیں اور شاہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انڈونیشیا میں صدر احمد سوئیکارنو کی رہنمائی میں بھی حکمران طبقے نے ملک کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ترکی کے نقش قدم پر لے جانے کی کوشش کی۔انڈونیشیا میں اگرچہ مغربیت کے خلاف رد عمل بھی ظاہر ہوتا رہا اور اسلامی تحریکیں اٹھتی رہیں، تاہم متجددانہ سر گرمیاں ہنوز جاری ہیں۔
تیونس میں حبیب بورقیبہ نے ۱۹۵۷ء میں صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی کمالی اصلاحات اورتجددکا آغاز کر دیا۔ تیونسی صدر مسیحی مشنریوں اور مستشرقین کے خیالات سے حد درجہ متاثر ہوا۔ اس نے قرآن میں تضادات ثابت کرنے کی کوشش کی اور قرآنی قصوں کو خرافات کا مجموعہ قرار دیا۔الجزائر کے ۱۹۶۳ء میں منتخب ہونے والے صدر احمد بن بلا جمال عبد الناصر کے دوستوں اور ہم خیالوں میں سے تھے۔ انہوں نے صدر ناصر ہی کی طرز پر دینی ذہن کو محدوداور حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ صدر کرنل معمر قذافی نے ۱۹۶۹ء میں زمام اقتدار سنبھالی اور بعض شرعی حدود کا نفاذ کیاتو مغربی پریس میں ان کو ایک کٹر مذہبی شخصیت کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔مستشرقین سے رابطہ کی بنا پران کا انقلابی دائرۂ فکر سیاست سے ہٹ کر دینی فکر میں انقلاب تک وسیع ہو گیا۔ انہوں نے یہ تصور قائم کر لیاکہ وہ اسلام جو کتاب وسنت سے ماخوذ ہے، اس انقلابی عہد کا ساتھ نہیں دے سکتا۔چنانچہ انہوں نے اسلام کو اپنے انقلابی ذہن کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ وہ اسلام کو عبادت تک محدود کر دینا چاہتے تھے ۔عبادت اور عام زندگی کے بارے میں ان کا تصورتیونسی صدر حبیب بورقیبہ سے بہت قریب ہے ۔حبیب بورقیبہ نے قرآن کے بارے میں شکوک وشبہات کا اظہار کیا۔معمر قذافی نے حدیث کوتختہ مشق بناتے ہوئے اسے مشکوک اور ناقابل اعتماد ثابت کرنے کی کوشش کی۔الغرض قذافی بھی پورے زور شور سے تجدد ومغربیت کے راستے پر ہو لیے۔۵۱لمحہ موجود تک تمام مسلم قیادت تجدد ومغربیت ہی کو کامیابی و کامرانی کا واحد راستہ سمجھتی ہے اوراس کلیے میں شاید ہی کوئی استثنا نظر آئے۔
جدید تعلیم یافتہ دانشوراورسکالرز
مسلم دنیا کے جدید تعلیم یافتہ دانشور اور سکالرزکی بھی ایک قابل لحاظ تعداد مستشرقین کے زیر اثر ہے۔ ان میں ایک بڑی تعدادنے یورپ کی یونیورسٹیوں میں مغربی اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا اور اپنے اساتذہ کے تصورات ونظریات اپنا لیے۔ ۵۲ ان کے نزدیک بھی مسلمانوں کی ترقی و کامرانی تجدد و مغربیت کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضورؐاور خلافت راشدہ کے زمانے تک اسلام ایک لبرل، ترقی پسند اور عقلیت پسند مذہب تھا، لیکن بعد میں فقہا اور ملاؤں نے اسے جامد اور متحجر دین بنا دیا۔ چنانچہ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ نام نہاد علما ومفسرین ہی ہماری تمام تر حرماں نصیبی اور پسماندگی کا اصل سبب ہیں۔ ایک دانشورنے لکھا ہے کہ سعودی عرب سے لے کر موریطانیہ تک اور انڈونیشیا سے لے کر پاکستان تک ہر مسلم ملک میں اہل اسلام زیست کی جنگ لڑرہے ہیں۔ ملا مسلمانوں کے تنزل وادبارکو مغربی اثرات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ جہاں تک ہنوز مغربی اثرات نہیں پہنچے، وہاں اب بھی اسلام کی گھناؤنی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا اس بات سے انکار کی کوئی معقول وجہ ہے کہ سب سے پسماندہ ممالک وہ نہیں جہاں یورپی تہذیب کی باد نسیم کے جھونکے نہیں پہنچے بلکہ بد نصیب وہ بلاد وامصار ہیں جہاں زمام اقتدار ملاؤں کے ہاتھ میں ہے۔ انہی کور چشموں کے سبب اسلام جمود کا شکار رہا اور اسے وقت کے مطابق ڈھلنے سے روکا جاتا رہا۔ عالم اسلام کونحوستوں اور لعنتوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں قرآن کی ان روایتی تعبیرات کو بھول جانا ہوگا جو راسخ العقیدہ ملاؤں نے صدیوں سے مسلط کر رکھی ہیں ۔ جس دن ہم اپنے طور پر قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، اس دن ہم اسلام کو بچانے نیز عورتوں کو چودہ سو سال کی محرومی و بد نصیبی سے نکال کر آزادی و مساوات کی روشنی میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ محبت و مسرت سے مذہب پر عمل کریں گے۔ زندگی سے اکتاہٹ اور بوریت ختم ہو جائے گی۔ نماز بھی ہو گی اور کھیل تماشا بھی۔ یوں ہم ایک دل پسند ہیرے کی طرح اسلام کی خوبصورت تعبیر ملاحظہ کر سکیں گے۔ ۵۳جدید تعلیم یافتہ دانشور اور سکالرزمستشرقین کی ہم نوائی میں اس تصور کے حامی ہو گئے کہ ترقی و تبدیلی، جو کہ قانون ارتقا کا جزو لا ینفک ہے، کواسلام پربھی لاگو ہونا چاہیے اور قدیم اسلام کی جگہ ایک جدید لبرل اسلام سامنے آنا چاہیے:
"Just as the Martin Luther broke down the barriers of dogma in Christianity and Moses Mendelssohn sought to bring a progressive reformed version of Judaism to the Jews, so Islam must also be recognized and given its place the by the Orthodox."(54)
مصر کے معروف دانشور اور سکالر ڈاکٹر طہ حسین نے مصریوں کو مغربی تہذیب اپنانے کی پر زور دعوت دی ۔وہ کہا کرتے تھے کہ مصری زندگی اپنے مظاہر کے اختلاف کے ساتھ خالص مغربی ہے۔ لہٰذا مصر کو مشرق کا حصہ اور مصری فکر کو ہندوستان یاچین کی طرح مشرقی فکر کہناکم عقلی اور سطحیت ہے۔ ہمیں اہل یورپ کے طریقہ پر چلنا چاہیے اور انہی کی سیرت و عادات کو اختیار کرنا چاہیے۔ درحقیقت عصر حاضر میں ہمیں یورپ سے ایسا رابطہ اور قرب چاہیے جو روز بروز بڑھتا رہے یہاں تک کہ ہم لفظ اور معنی حقیقت اور شکل ہر اعتبار یورپ کا ایک حصہ بن جائیں۔ ۵۵ ڈاکٹر طہ حسین عربی ادب کو دینی علوم کے تعلق سے یکسر آزاد کر دینے کے حامی ہیں۔وہ اس سلسلہ میں تحقیق پر ،قومی احساسات اورمذہبی رجحانات و میلانات کوبالائے طاق رکھ کر اس فلسفیانہ طریقہ کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں جس کی ابتداڈیکارٹ نے کی تھی۔ ۵۶ ڈاکٹر صاحب اس بات سے انکاری ہیں کہ کعبہ کی بنیاد ابراہیم اور اسمعیل علیھم السلام نے رکھی تھی،بلکہ ان کے نزدیک یہ دونوں شخصیتیں کوئی تاریخی وجود ہی نہیں رکھتیں۔آپ کے خیال میں قرآن کی سات مشہور قرأتیں بھی حضورؐ سے ماخوذنہیں ہیں۔۵۷
پاکستانی اسکالراور دانشور ڈاکٹر فضل الرحمن کے نزدیک مسلمانوں کو مغربیت اختیار کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ مغربی تہذ یب اپنانے کے باوجود مسلمان مکمل مسلمان رہ سکتے ہیں۔ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ بعض مسلم اورغیر مسلم اسلام کو ایک مخصوص طرززندگی سمجھتے ہیں جس میں مشکل ہی سے کوئی تبدیلی ممکن ہے، حالانکہ اسلام کے بہت سے غیر مسلم طالب علم مثلاً پروفیسر گسٹاف اے وان گرونیبام کے نزدیک اسلام دراصل کسی تہذیب و ثقافت کا نام نہیں بلکہ قرآن و سنت کے فراہم کردہ کچھ اصول و ضوابط کا نام ہے جس میں وقت اور ضروریات سے توافق وتطابق کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ۵۸ ڈاکٹر فضل الرحمن قرآن میں بیان کردہ قصصِ انبیاء کی تفصیلات کو بعینہ وحی خداوندی ماننا ضروری خیال نہیں کرتے۔ ۵۹ان کے مطابق مسلمانوں میں پانچ نمازوں کا تصور حدیث کی بعد میں اٹھنے والی لہر کانتیجہ ہے جبکہ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں۔ ۶۰
چونکہ حدیث اور جدید مغربی تہذیب کو یکجا کرنا ممکن نہیں اور بقول علامہ محمد اسد حدیث کو نظر انداز کر کے قرآنی تعلیمات کو آسانی سے مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے ،۶۱ لہٰذاحدیث پر اعتراض جدید تعلیم یافتہ مسلم دانشوروں کے ہاں ایک فیشن بن گیا۔ وہ بڑے زور و شور سے حدیث کو ناقابل اعتبار روایات پر مبنی اوراسلام کاغیر ضروری حصہ قرار دینے لگے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن کے نزدیکحدیث ایک تاریخی افسانہ ہے جس کا مواد مختلف ذرائع سے اکٹھا کیا گیا۔۶۲ سنت محض ابتدائی مسلم سوسائٹی کی عملی زندگی کا لفظی اظہار ہے اور ایک زندہ معاشرے کے طرز عمل میں وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بنا بریں حدیث کوئی دائمی نمونہ عمل نہیں۔۶۳ غلام احمد پرویز بھی احادیث کو فرضی اور ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق آج احادیث کے نام سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے، یہ محض مسلمانوں میں مروج باتیں تھیں جن کو غلط طور پر حضور کی جانب منسوب کیا جاتا تھا ۔ بعد ازاں امام بخاری اور دیگر حضرات نے ان باتوں کو جمع کر کے کتبِ احادیث کی شکل دے دی ۔۶۴مستشرقین سے متاثر ہو کر اور بھی متعددمسلم دانشوروں نے حدیث کاانکار کیا ہے۔ ۶۵
حوالہ جات و حواشی
1. See: "Supernatural Religion", published by Longman, London,1874, Vol. II., pp. 491-492.
2. See for detail: Kant, Immanuel, "Religion within the Limits of Reason Alone", New York, 1960.
3. Vide, Muier, William, "Muhammad and Islam", London Religion Trackt society, N.D., pp. 22-24. Mohammad Khalifa, "The Sublime Quran and Orientalism", London & New York, 1983, p.112.
سر سید احمد خاں،سیرت محمدی، لاہور، مقبول اکیڈمی،۱۹۹۷،ص۲۳۲۔۲۳۳۔
4. Watt, W. Montgomery, "Muhammad: Prophet and Statesman", Oxford University Press, 1958, pp.14-17.
5. Hume, David, "Enquiries concerning the Human Understanding", edited by L.A. Selly, Bigge 2nd ed; Oxford, 1893, p.119.
6. Ibid.p.114.
7. Lawton, J.S. Dr., "Miracles and Revelation", London, 1959, p. 84.
8. Ibid. p. 100.
9. "Supernatural Religion", Op. Cit.. Vol.II. p.486.
10. Bashir Ahmad Siddiqi, Dr. Professor, "Modern Trends in Tafsir Literature-Miracles", Lahore, Facilty of Islamic and Oriental Learning, University of the Punjab, 1988, p.8.
11. Sale, George, "The Koran", New York, 1890, p .50.
12. Watt. W. Montgomery, Op. Cit. p. 39. "Encyclopaedia of Religion and Ethics|, edited by James Hastings, New York, Charles Scribner's Sons,1930, Vol. X, p. 540. Brown, Daniel, "A New Introduction to Islam", United Kingdom, Blackwell, 2004, p. 65. "The New Encyclopaedia Britannica", 15th edition,1986, Vol. 22, p. 9. Bell, Richard, "Introdution to the Quran", Edinburgh University Press, 1963, pp.161-163.
13. Jeffery, Arthur, "Muhammad and his Religion", Indiana Polus, 1979, p. 47.
14. Idem, "Materials for the History of the Texst of the Quran", Leiden, E. J. Brill, 1937, pp. 3-10.
15. Palmer, E. :The Koran with an Introduction" by R Nicholson, London, Oxford University press,1928,p,53.
۱۶۔ رحمت اللہ کیرانوی، بائبل سے قرآن تک(مترجم،اکبر علی)کراچی، مکتبہ دارلعلوم،۱۳۸۹ھ،جلددوم،ص۳۶۵۔
17. Goldziher, Ignaz, "Muslim Studies", Translated by C.R.Barber and S.M.Stern, Chicago; IL Aldine Publishing, 1973, Vol.II, 18. Guillaume, Alferd, "The Traditions of Islam", Beirut, Khayats, 1960, p.15.
18. Tor Andrae, "Muhammasd, The man and his Faith", translated from German by Theophil Menzel, London,George Allen and Unwin,1956, pp.143, 191.
19. Muir, William, Op.Cit.p.47. Watt, W. Montgomery, Op. Cit. p.14. Gib, H.A.R, "Mohammemanism", London, Oxford, 1964, p. 25.
20. Muir, William, Op,Cit.p.126.
21. Tor Andrae, Op. Cit. p.147. Sale, George, Op. Cit. p. 38. Watt, W. Montgomery,Op.Cit.p.105.
22. Bell, Richard, Op.Cit. pp.156-161. Muir,William, "The life of Mahomet", London, Smith, Elder & Co.1877, Vol.2.pp.141-145.
23. Watt, W. Montgomery, Op. Cit. p.108.
24. Tor Andrae, Op.Cit. p.147. Sale, George,Op. Cit. p.38. Menezes,F.J.L, "The Life and Religion of Mohammad, the Prophet of Arabian Sands", London,1911, pp. 63,165. Wollaston, A. N, "The Religion of the Koran", Lahore, Sh. Muhammad Asharf, 1965, p.27.
25. Watt, W. Montomery, "Muhammad at Madina", Karachi, Oxford University Press, 1981, p.277.
26. Mohammad Khalifa, Op.Cit. p.157.
27. Shacht, J. "Introduction to Islamic Law", Oxford, 1964,p.202.
28. Coulson, N. J., "Conflicts and Tentions in Islamic Jurisprudence", London, The University of Chicago press, N.D., p.78. "Encyclopedoia of Crime and Justice", New York, The Free Press, 1983, Vol.1, p.194.
29. "The New Encyclopaedia Britannica", Chicago, 1986, Vol.18, pp.996-997.
30. Kenneth Cragg, "The Call of Minaret", New York, Oxford University Press, 1956, p.17.
31. Idem, "Islamic Surveys-3: Counsels in Contemporary Islam", Edinburgh, Edinburgh University Press,1965,p.107.
32. Idem, "The Dome and the Rock: Jerusalem Studies in Islam", S.P. C. K; London, 1964,p.135.
33. Hitti, Philip. K, "Islam and the West", New Jersey, 1962, p.21.
34. Smith, Welfred Cantwell, "Islam in Modern History", New Jersey, Princeton University Press, 1957, pp.178,204.
35. Ibid. pp. 273,274.
36. Goitien, S. D.. "Jews and Arabs: Their Contacts through the Ages", New York, Schockan books, 1955, pp.129-130.
37. Nadave Safran, "Egypt in Search of Political Community: An Analysis of the Intellectual and Political Evolution of Egypt", 1804-1952. Cambridge, Havard University Press, 1961,p.80.
38. Ibid,pp.95-97.
39. Vide, Muhammad Imran Moulana, "Distortions about Islam in the West", Lahore. Malik Siraj & Sons,1979,p.13.
۴۰۔ اسلامی تاریخ و تہذیب سے متعلق استشراقی تحریروں کے مبنی بر تعصب و عناد ہونے کا اندازہ اس حقیقت سے لگایاجا سکتاہے کہ خود بہت سے مغربی زعماء اور اہل قلم نے اس ضمن میں استشراقی تحرورں کو مسلمانوں کیخلاف صلیبی جنگوں کے تسلل کا نام دیا ہے۔مثلاًملاحظہ ہو:السباعی، محمد مصطفی،ڈاکٹر،السنۃ ومکانتہا فیالتشریع الا سلامی،القاہرہ ،مکتبہ دارلعروبہ شارع الجمہوریہ،۱۹۶۱،ص۳۲۔
Loon Handrik Van, "Tolerance", New York, The Sun Dial Press, 1939, p.114.
41. Wright, Thomas, "Early Christianity in Arabia", London, 1855, p,152.
42. Hitti, P. K. "History of the Arabs", London , Macmillan, 1968, p.147.
مذکورہ حوالے سے J.J.Saunders بھی ہٹی کا ہمنوا ہے۔ دیکھیے:
Saunders, "A History of Medievel Islam", London, Routledge and Kegan Paul, 1965, p. 14.
۴۳۔ حامدی، خلیل احمد(مرتب)،نظام اسلام مشاہیر اسلام کی نظر میں،لاہور،اسلامک پبلیکیشنز،۱۹۶۳،ص۴۵۲۔
۴۴۔ ابو الحسن علی ندوی، مولانا،مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش،کراچی، مجلس نشریات اسلام،۱۹۸۱، ص۲۶۵۔۲۶۶۔
45. Maryam Jameelah, "Islam and Modernism", Lahore, 1977, p.239.
46. Ziya Gokalp, "Turkish Nationalism and Western Civilization", New York, 1959, pp. 60,271,302.
47. Armstrong, H.G, "The Gray Wolf", New York, Capricon Books, 1961, pp.199-200.
48. Irfan Orga Margarate, "Ataturk", London, 1962, p. 273.
49. Ibid. pp.237,238,297.
50. Ibid. p. 280.
ترکوں کو اپنی اسلامی شناخت سے دور ہٹانے،اسلامی اتحاد کو ضرب لگانے کے خاطر انہیں اپنی اصلی قومیت کااحساس دلانے کے لیے،جس کا دارامدار نسل اور مادری زبان پر ہے،اورانہیں یہ باور کرانے کے لیے کہ وہترک پہلے ہیں اور مسلمان بعد میں، مستشرقین کی کاوشیں کلیدی کردار کی حامل ہیں۔ ان استشراقی کوششوں کے قدرے تفصیلی مطالعہ کے لیے مثال کے طور پر دیکھؤ: اکمل ایوبی،ڈاکٹر،مستشرقین اور تاریخ ترکی،در،ماہنامہ ’معارف‘اعظم گڑھ،اکتوبر۱۹۸۳ء،ص۲۵۱۔۲۶۰۔
۵۱۔ عالم اسلام کے حکمران طبقہ کے استشراقی ومغربی فکرسے تاثر کے نتیجہ میں تجددو مغربیت کی طرف راغب ہونے سے متعلق یہ نکات مولانا ابوالحسن علی ندوی کی،مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش ، سے اخذکے کیے گئے ہیں۔تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوں مذکورہ کتاب کے صفحات۱۶۲۔۲۲۵۔
52. See for detail: Smith, Wilferd Cantwell, Op.Cit .pp.55-73.
53. Jafri, Fareed S, "The Need for a Re-evaluation of Islam in Pakistan", the Pakistan Times Lahore, August 11,1967.
54. Fyzee, Asaf A, "A Modern Approach to Islam", Bombay, Asia publishing House, 1963, p.107.
۵۵۔ طہ حسین،ڈاکٹر،مستقبل الثقافۃ فی مصر،قاہرہ،۱۹۳۸ء،ص۳۱۔۴۴۔
۵۶۔ وہی مصنف، الادب الجاھلی،قاہرہ، ۱۹۲۷ء،ص۶۵۔۶۸۔
۵۷۔ چارلس سی آدم، اسلام اور تحریک تجدد مصر میں (مترجم،عبدالمجید سالک)، لاہور، مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۲۔ ص ۳۷۰، ۳۷۳، ۳۷۴۔
58. Fazlu-Rahman, Dr, "What is Islamic Culture?", The Light, Lahore, March 24,1973, p.5.
59. Idem, Weidenfield and Nicholson, London, 1996, p.16.
60. Ibid.p.36.
61. Muhammad Asad, "Islam at the Cross Roads:, Lahore, Arafat Publications, 1955,pp.112-130.
62. Fazlu-Rahman, Dr, Weidenfield and Nicholson, Op.Cit. p.14.
63. Ibid. p.56.
۶۴۔ پرویز ،غلام احمد ، مطالب الفرقان ، جلد چہارم ،لاہور،ادارہ طلوع اسلام،۱۹۸۱ء ،ص۳۴۳۔۳۵۳۔
’’حیات سدید‘‘ کے ناسدید پہلو (۲)
چوہدری محمد یوسف ایڈووکیٹ
مجموعی تاثر
کتاب پر تفصیلی اظہار سے پہلے اپنے تاسف کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ کتاب کی ترتیب میں جناب اعظم صاحب کی محنت و ریاضت اور جناب مجید نظامی کی پیش لفظی سطور نے جو مجموعی تاثر، کم از کم میرے ذہن پر چھوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب کی ترتیب کا منشا سید مودودی کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے۔ اس غرض کے لیے جنابِ مولف نے پوری فنی مہارت سے کام لیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بنیادی مواد (خطوط) کی مکمل فائل کا جماعت کے مرکز میں پہنچنے کا سراغ لگا یا ہے اور پھر اس کی عدم دستیابی کا تاثر دیا۔ ساتھ ہی جماعت کے ایک دوسری سطح کے مگر نہایت بلند قامت و پختہ کردار کے بزرگ جناب محمد یوسف خان سے اس فائل کے، پانچ ہزار روپے کے عوض حاصل ہونے کا تذکرہ کیا مگر اس کی مزید پستی کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ یہ بہت ناقص فوٹو کاپیاں تھیں جن سے استفادہ بہت مشکل تھا۔ (صفحہ نمبر ۳۴۲) اس کے باوجود وہ اس میں سے کافی خطوط پڑھنے اور پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی میں، کہاں کہاں وہ انحراف کی حدوں سے بچے رہے اور کہاں کہاں ان حدود کو پار کر گئے، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ خطوط کی اصل فائل بقول مولف دستیاب نہیں۔ دستیاب فوٹو کاپی قابل خواندگی نہیں۔ ناقابل خواندہ تحریروں کو پڑھنے کے لیے شاید برآمد شدہ جدید آلات سے مدد لی گئی ہو۔ اس کا مولف نے ذکر نہیں کیا۔ اگر کرتے تو ہم بھی جدید آلات کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے مگر اس کے لیے بھی فائل کا مولف سے دستیاب ہونا شرط ہو گا۔
یہ بھی صاف ہے کہ خطوط کی ناقص نقول سے بہتر نقول کی صحت مندانہ تیاری کے عمل سے جناب مجید نظامی کو کوئی دلچسپی ہے نہ ہی ارباب جماعت کو۔ یہ در دِ سر جناب سلیم منصور کے بعد، ادارہ معارف اسلامی کے لائبریرین جناب پروفیسرِ ظفر حجازی صاحب کا ہو سکتا ہے۔ جناب لیاقت بلوچ اور جناب حافظ محمد ادریس تو پہلے ہی کتاب کا قصیدہ کتاب کی وصولی کی رسید لکھتے ہوئے لکھ چکے ہیں۔ وہ اس سے رجوع کریں گے یا نہیں، کچھ انتظار کے بعد واضح ہو گا۔ اس پڑتول میں میری مشکل ریسورس ریفرینس ((resource references تک رسائی مسئلہ ہو گی۔
اس پس منظر میں، حیات سدید کے مولف کے پیرایے میں جو تضادات پائے جاتے ہیں، وہ گہرے اور تعداد میں وافر ہیں۔ ہم ان کا موقع بموقع ذکر کریں گے، البتہ کتاب کی ترتیب میں پائی جانب والی چابک دستی کو سامنے لانے کو اولیت دیں گے۔ یہ واضح ہے کہ کتاب میں پیش کردہ تاریخی حقائق پر، آج قریب قریب ایک صدی کے بعد، قطعیت کے ساتھ کچھ کہنے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں۔ جناب کے ایم اعظم صاحب نے اپنے والد محترم چوہدری نیاز علی خان، علامہ اقبال، ابوالحسن علی ندوی،سید نذیر نیازی کی روایات کو الگ رکھ کر جناب چودھری غلام احمد پرویز، ان کے ہمدم دیرینہ جناب شیخ سراج الحق اور اسی طرح کے بعض دوسرے اصحاب کی روایات کو ترجیح دینے میں صریحاً زیادتی فرمائی ہے۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ چوہدری نیاز علی خان صاحب نے مولانا مودودی کو دارالاسلام پٹھانکوٹ میں مدعو کیا تھا یا علامہ اقبال نے۔ مجید نظامی تو پہلے ہی مولانا کے اقبال کے ساتھ قرب کے قصے گڑھنے کا کہہ چکے تھے۔ اس تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے خود حیاتِ سدید میں مذکورہ اصحاب کے شواہد کافی سے زیادہ تھے۔ جناب پرویز کو میدان میں لا کر بات مجید نظامی سے آگے نکل گئی۔ مولانا مودودی کی پٹھان کوٹ منتقلی کی تجویز کے ایک تیسرے دعوے دار جناب غلام احمد پرویز بن گئے۔پون صدی بعد تیسرا دعوے دار کہاں سے آ گیا۔ اس الجھاؤ آفرینی سے جناب کے ایم اعظم کا کیا مقصود ہے؟ پوری کتاب سے گزر جائیے تو بھی واضح نہیں ہو گا۔ الجھاؤ فزونی کے فن کا وکالت میں ہمیں کئی بار تجربہ ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے کیس کو کمزور دیکھتے ہیں تو اس کو اس طرح پیش کرنا شروع کرتے ہیں کہ جج صاحب کا دماغ ایک سے نکل کر دوسری الجھن کا شکار ہو جائے۔ اس طرح مقصود یہ ہوتا ہے کہ جج لگا تار الجھاؤ سے عاجز آ کر عارضی سا ریلیف دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جناب کے ایم صاحب اسی طرح کی فنی تکنیک کو قارئین پر آزما رہے ہیں۔ پوری کتاب اس طرح کی الجھنوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہر حال مصنف کی فنکاری کی داد دینا پڑتی ہے۔
مسئلہ کی نوعیت ہم نے اوپر واضح کر دی ہے۔ ہم جناب پرویز کے دعوے کو یکسر نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حیات سدید میں پرویز صاحب کے حوالے سے کہانی تین مرحلوں میں بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو جناب پرویز دارالاسلام کے قیام کے موقع پر، ادارے کا تعارفی مضمون طلوع اسلام میں شائع کرتے ہیں۔ یہ مضمون اگست ۱۹۳۹ء میں چھپا۔ کہانی کے دوسرے حصے میں پہلی بار وہ دارالاسلام کے لیے اقبال کی جانب سے اپنانام تجویز کرنے اور قائد اعظم کی جانب سے ان کو اس کام کے لیے پٹھانکوٹ جانے کی اجازت دینے سے انکار کی بات کی گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مولانا کا نام تجویز کر کے اقبال کو منظوری کے لیے لکھ بھیجا۔ کہانی کے دوسرے مرحلے کے بیان میں وہ بعض خطوط کا ذکر کرتے ہیں۔ حیات سدید کے صفحہ ۱۹۵ میں ان خطوط کا ذکر دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہانی کے اس حصے کو ادھورا چھوڑنے کے بجائے حیات سدید کے صفحہ نمبر ۱۹۵ پر مذکورہ تحریروں کو حاصل کر کے شامل کتاب کیا جانا چاہیے تھا۔ کتاب میں پرویز صاحب کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ
’’چوہدری نیاز علی خان کے اصرار و تقاضا نے علامہ صاحب کو مجبور کر دیا تو لا چار انہوں نے پرویز صاحب کو دہلی میں لکھا کہ آپ دارالاسلام چلے جائیں۔‘‘
قائد اعظم کی جانب سے اس تجویز پر انکار کے بعد پرویز صاحب نے حضرت علامہ اقبال کو عریضہ ارسال کیا کہ مجھے تو کوئی عذر نہ تھا لیکن قائد اعظم کی طرف سے No ہے۔‘‘
پرویز صاحب مزید لکھتے ہیں کہ :
’’پرویز صاحب نے حضرت علامہ کو لکھا کہ آپ نے مولانا مودودی صاحب کا ’’دو قومی نظریہ‘‘تو پڑھا ہوگا، اگر وہ دارالاسلام چلے جائیں تو بہتر ہو گا۔علامہ نے جواباً لکھوایا کہ ہاں ایسا ہو جائے تو موزوں ہے۔چنانچہ یہاں سے دارالاسلام کے لیے مولانا مودودی صاحب کے متعلق بات چلی۔‘‘
اوپر درج اقتباسات میں جن خطوط کا ذکر آیا، ہے ان کی تفصیل اس طرح ہے۔
۱۔ علامہ اقبال کا خط بنام غلام احمد پرویز جس میں علامہ نے جناب پرویز کو دارالاسلام جانے کے لیے کہا۔
۲۔ جواب کے طور پر قائد اعظم کا خط بنام علامہ اقبال جس میں قائد نے تجویز سے اختلاف کیا۔
۳۔ پرویز کا خط علامہ اقبال کے نام جس میں پرویز صاحب نے دارالاسلام کے لیے اپنے بجائے مولانا کا نام تجویز کیا۔
۴۔ پرویز کے جواب میں علامہ اقبال کا خط جس میں مولانا مودودی کے نام کی تائید کی گئی۔
مولف کتاب جناب کے ایم اعظم صاحب نے ان چار خطوط کی جستجو نہیں کی۔ پوری کتاب میں کہیں اس جستجو کا ذکر نہیں۔ خط ایسے اہم لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں کہ ان کے محفوظ ہونے کا قوی امکان ہے۔ یہ خطوط تحریری شہادت کے درجے کی چیز ہیں۔ جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ یہ خطوط دستیاب نہیں، اس وقت تک ان واقعات پر زبانی شہادت کسی طرح بھی قابل لحاظ نہیں ہو سکتی۔ ہم جناب مجید نظامی کی حد تک نہیں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قصے گڑھے گئے۔ البتہ واقعات کے اثبات میں یہ معمول کے قواعد ہیں۔ان کو نظر انداز کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا درست نظر نہیں آتا۔
کہانی کے دوسرے حصے میں پرویز صاحب نے اپنے متعلقہ حصے کی تمام تر تفصیلات پہلی بار بیان کی ہیں۔ اپنے اولین مضمون میں ان کا کہیں کسی حد تک بھی ذکر نہیں کیا۔ تیسرا حصہ ان کے غیر نشر شدہ ٹی وی انٹرویو کی صورت میں ہے۔ یہاں کہانی بیان کرتے ہوئے تمام خطوط کا ذکر غائب کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی کہانی مرحلہ وار مرتب ہوئی ہے۔ اس میں ارتقا پایا جاتا ہے۔ جب تک دوسرے بیان میں مذکورہ خطوط سامنے نہ ہوں، ان پر کلام تقاضائے احتیاط کے خلاف ہو گا۔ بیان میں اس طرح کی امپرومنٹ کسی طور پر قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ فن وکالت میں تو اسے after thought کہا جاتا ہے۔
علاوہ ازیں یہ امر بھی اہم ہے کہ پرویز صاحب کے صورت حال میں پیش کردہ مشاہدات کو دیکھنے پر قارئین ایک موقع پر سخت حیرانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پرویزی حلقے اور مودودی صاحب کے ما بین حدیث کی شرعی حیثیت کے بارے میں طویل مناقشے سے ہر کوئی واقف ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی طویل حیات میں ایک ہی مناظرہ کیا ہے۔ وہ مناظرہ سے گریز کی روش پر قائم رہے۔ اس میں ایک ہی استثنا ہے۔ یہ پرویزی فکر حدیث پر ہے۔ اس مناظرے میں انہوں نے خوب جم کر حدیث کا دفاع کیا ہے۔ اس مناظرے کے پس منظر کا بیان کر دیا جائے تو یہ واضح ہو سکتا ہے کہ مولانا نے یہ مناظرہ کرنے کا یہ استثنا کیوں اختیار کیا۔دراصل اس دور میں مولانا کی تحریروں میں قرآن پر تکرار سے زور پایا جاتا ہے۔ حدیث پر زور شاید ہی کہیں نظر آئے۔ یہی کیفیت پرویز کی تحریروں میں بڑی نمایاں تھی۔ اس سے پڑھے لکھے طبقے میں یہ تاثر یا اشتباہ پایا جاتا تھا کہ شاید مولانا مودودی اور پرویز کا حدیث کی حجیت کے بارے میں نقطہ نظر ملتا جلتا ہے۔ اس اشتباہ کے تحت ہی جناب پرویز کے دست راست ڈاکٹر عبدالودود نے مولا نا مودودی سے خط و کتابت کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ یہی تحریری مباحثہ ترجمان القرآن میں باقاعدگی سے چھپا اور پھر اسے ’’سنت کی آئینی حیثیت‘‘ کے عنوان کے تحت کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔اس طرح طلوع اسلام اور ترجمان القرآن میں اتنا واضح اختلاف اور بعد واضح طور پر معروف ہوا کہ جب حیاتِ سدید سے یہ بات سامنے آئی کہ مولانا مودودی کا ایک زمانے میں طلوع اسلام کی ادارت کے لیے نام تجویز ہوا۔ قاری کے لیے یہ معلوم کر کے حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پوری کتاب میں کہیں بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ قاری کو اس طرح حیرانی میں مبتلاکرنے سے مصنف کا کیا منشا ہے۔
حیرانی میں مبتلا قاری یہ پوچھتا ہے کہ اگر اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو آج پون صدی بعد، طلوع اسلام کی ادارت کے بارے میں پرانی تجویز کے ذکر سے مولانا مرحوم کے بعد کے نقطہ نظر اور طرز عمل کو فرو تر کرنے کی کوشش کے سوا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کہ کیا اس کے ذکر سے مولانا کو کوئی ایوارڈ دیا جانا مقصود ہے؟ کیا ان کے معنوی جانشینوں کو آج بھی طلوعِ اسلام کی ادارت میں حصہ لینے کو کوئی موقع دیا جاسکتا ہے؟ یقیناًایسا ممکن نہیں تو پھر یہ ذکر کسی طور موقع ومحل کے مطابق معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا کوثر نیازی کا جماعت اور مولا نا سے اولین وابستگی کا ذکر کیا جائے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ مولانا مودودی مرحوم و مغفور نے زندگی بھر مولانا کوثر نیازی کے سوا کسی شخص سے ملنے سے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ جنرل اعظم اور مصطفی کھر تک کو بھی ملنے سے گریز نہیں کیا۔ مگر وہ اس جہاں سے مولانا کوثر نیازی سے اتنا دکھی گئے ہیں کہ اپنی حیاتِ مستعار کے آخری لمحات میں بھی کوثر نیازی کو ملنے کی اجازت نہ دی۔
فیصلہ کن مواد .....خطوط
ویسے بھی کتاب میں سید نذیر نیازی کا خط، مولانا مودودی اور چوہدری نیاز علی کے (چالیس) باہمی( خطوط صورت حال میں متنازعہ امورطے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ البتہ مولانا مودودی کی جانب سے نذیر نیازی کے نام دو خطوط کو شامل کر لیں تو صورت حال طے کرنے میں کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ مولانا کے یہ خطوط ہم آخر پر بطور ضمیمہ شامل کر رہے ہیں۔ بہر حال جناب پرویز کی کہانی یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اولاً غلام احمد پرویز کو دارالاسلام میں منتقل ہونے کے لیے تجویز کیا۔ جناب پرویز اس پر آمادہ تھے مگر قائد اعظم نے پرویز صاحب کو دہلی چھوڑنے کی اجازت نہ دی۔ پھر مولانا مودودی کا نام علامہ اقبال کو پرویز نے تجویز کیا جسے علامہ نے مان لیااور مزید پیش رفت ہوئی۔
کتاب میں یہ بھی کہا گیا کہ اقبال کے بارے میں مولانا مودودی کے خیالات دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتے رہے۔ علامہ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ مولانا مودودی کو دارالاسلام کے پروجیکٹ کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ کے نزدیک مولانا مودودی ملا تھے اور بادشاہی مسجد کے خطیب سے زیادہ کے مقام کے مستحق نہیں تھے۔ نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ مولانا کو پٹھان کوٹ لانے میں اقبال پر معروضی حالات کے علاوہ نیاز علی خان کا ’’اصرار‘‘ ہی اصل ہے، وگرنہ علامہ تو مولانا کو دارالاسلام پروجیکٹ کے لیے کسی طرح راہ دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ نیاز علی خان کا بر صغیر کے دیگر علما کی طرح مولانا سے بھی دیرینہ رابطہ تھا۔ علما کے ساتھ چوہدری نیاز علی خان کے خط و کتابت کو دیکھنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ علما میں سے مولانا مودودی سے زیادہ کسی اور نے چوہدری صاحب کے خطوط کو اہمیت نہیں دی۔ دارالاسلام کی ہیئت طے کرنے میں چوہدری نیاز علی خان نے بہت سے لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ کتاب کے صفحہ نمبر ۳۴۵ پر ابوالکلام آزاد کا خط بنام چوہدری نیاز علی خان موجود ہے۔ خط میں مطلوب مشورہ سے گریز کیا گیا ہے یا مشورہ دیا گیا ہے، ہم کچھ کہے بغیر خط کے اہم حصے درج کر رہے ہیں۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں:
’’خط پہنچا۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا خط آیا تھا جس میں آپ نے بعض انتظامات کی اطلاع دی تھی اور میں نے اس کے جواب میں لکھ دیا تھا کہ یہ انتظامات بہتر ہیں۔ اللہ آپ کی مساعی مشکور فرمائے۔
قرآنی ادارے کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے لیے کسی مضمون کا لکھ دینا یا کسی نقشہِ نصاب کا بنا دینا مفید ہو سکے۔ قرآن کے لیے نصاب تعلیم بجز قرآن کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اصل سوال اشخاص کا ہے، اور اس روئے تربیت کا جو کسی حلقہ میں پیدا ہو جائے۔ اگر اس بارے میں آپ بر وقت میر ے مشورے کے طالب ہوں گے تو جو کچھ مشورہ دے سکتا ہوں، اس میں حتی الوسع کوتاہی نہیں ہو گی۔
اس قسم کے ارادوں کا مجھ سے بڑھ کر استقبال کرنے والا کوئی نہ ہو گا۔ لیکن زمانے کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ میں خود اپنی جانب سے پیش قدمی کا قصد نہیں کر سکتا۔ کوئی طلب و امتیاز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو خود بھی بڑھنا ضروری سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی مشکور فرمائے۔کام کیے جائیے اور جب نفاذ کا وقت آئے، تعین کے ساتھ مرتب کار کی نسبت اطلاع دیجیے۔ میں جو کچھ مشورہ دے سکتا ہوں، ضرور دوں گا۔ ‘‘
کتاب کے صفحات ۳۷۹ سے ۳۹۵ تک مولانا ابوالحسن ندوی اور چوہدری نیاز علی کے چودہ خطوط شامل ہیں۔ ان سب کو پڑھ جائیے۔ رسمی دعا و حوصلہ افزائی کے سوا کم ہی لکھنے کا کچھ تکلف نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کا صرف ایک خط شامل کتاب ہے۔ خط بہت مختصرہے مگر علامہ نے کھل کر لکھا ہے۔ خط اس لائق ہے کہ یہاں نقل کر دیا جائے۔ ویسے بھی تبرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ خط کتاب کے صفحہ نمبر۳۴۴پر شیخ عطا ء اللہ کے اقبال نامہ کے حوالہ سے دیا گیا ہے۔
’’لاہور
۲۰۔جولائی ۱۹۳۷ء
جناب چوہدری صاحب!
آپ کا خط ابھی ملا ہے۔ آم اس سے پہلے مل گئے تھے جو نہایت شیریں ہیں۔ نیازی صاحب کے ہاتھ سے رسید لکھوا کر ارسال کر چکا ہوں۔ مہربانی کر کے اگر ممکن ہو تو اور آم اسی قسم کے ارسال کیجیے۔
آپ ضرور تشریف لائیں، میں آپ سے ادارہ کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اسلام کے لیے ملک میں نازک زمانہ آ رہا ہے۔ جن لوگوں کو احساس ہے، ان کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش اس ملک میں کریں۔ انشاء اللہ آپ کا ادارہ اس مقصد کو باحسن وجوہ پورا کرے گا۔علما میں مداہنت آگئی ہے۔ یہ گروہ حق کہنے سے ڈرتا ہے۔ صوفیہ اسلام سے بے پروا اور حکام کے تصرف میں ہیں۔ اخبار نویس اور آج کل کے تعلیم یافتہ لیڈر خود غرض ہیں اور ذاتی منفعت و عزت کے سوا کوئی مقصد ان کی زندگی کا نہیں۔ عوام میں جذبہ موجود ہے مگر ان کا کوئی بے غرض رہنما نہیں ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ امید ہے آپ کا مزاج بخیر ہو گا۔‘‘
کتاب میں شامل خطوط کی کل تعداد ۱۵۰ ہے۔ ان میں ۴۰ خطوط چوہدری نیاز علی خان اور مولانا مودودی کے ما بین ہیں۔ اس طرح ہر دو بزرگوں کے درمیان خطوط کا سلسلہ کسی دیگر بزرگ کے مقابلے پر کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ان خطوط میں دو طرفہ دلجمعی کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، وہ دیگر خطوط میں کہیں کہیں ہی نظر آتی ہے۔ ان خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دو حضرات کو زیر بحث موضوع (دارالاسلام) سے کس قدر گہری دلچسپی ہے۔ اس سلسلہ کلام کی ابتدا ۲۰ ستمبر۱۹۳۵ ہے۔ آخری خط ۶ جنوری ۱۹۳۸ء کا ہے۔ ۲۳ خطوط چوہدری نیاز علی نے مولانا مودودی کے نام لکھے، جب کہ مولانا مودودی نے ۱۶ خط لکھے ہیں۔ یہ خطوط کتاب کے صفحات ۴۸۲ سے ۵۵۲ پر ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب میں صفحہ ۱۲۶ پر دارالاسلام پر چھبیس صفحے کا وہ خاکہ شامل ہے جو ادارہ دارالاسلام کی بنیاد بنا۔ یہ مولانا مودودی کا مرتب کردہ ہے۔
اس خط و کتابت سے اندازہ ہوتا ہے کہ دارالاسلام کی نوعیت کی خدمت کا ذہن میں آتے ہی چوہدری نیاز علی خان نے مولانا مودودی سے رابطہ استور کیا۔ کتاب میں شامل خطوط کی رو سے قدیم ترین خط مولانا مودودی سے متعلق ہی ہے۔ اولین خط ۲۰ ستمبر ۱۹۳۵ء کاہے۔ جنابِ چوہدری نیاز علی خان اسی سال ریٹائر ہوئے۔ ریٹائر ہوتے ہی دارالاسلام کا غم شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی اولین رابطوں میں مولانا مودودی کوفوقیت حاصل ہے۔ دارالاسلام کے قیام اور اس کی عملی تشکیل میں علامہ اقبال اور مولانا مودودی نے سب سے زیادہ موثر حصہ لیا۔ دارالاسلام ٹرسٹ کی رجسٹریشن ۴ مارچ ۱۹۳۶ء کو ہوئی۔ مولانا مودودی ساتویں ٹرسٹی تھے۔ اقبال ٹرسٹیوں میں بوجوہ شامل نہ ہوئے، مگر ہمیشہ شریک مشورہ رہے۔ دارالاسلام میں قیام کے جامعہ ازہر مصر کو جو مکتوب علامہ کے دستخطوں سے ارسال کیا گیا، اس کا عربی متن مولانا مودودی کا مرتب کردہ تھا۔ حیدرآباد دکن سے دارالاسلام منتقلی تو بہت بعد کی بات ہے، مگر ادارے کے جملہ عملی تنظیمی کام، مولانا ہی انجام دیتے تھے۔ تمام ڈرافٹ حیدرآباد دکن ہی سے تیار ہو کر آتے تھے۔ چوہدری نیاز علی ان ڈرافٹوں کو خود قبول بھی کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی دکھاتے۔ چوہدری نیاز علی اور مولانا مودودی کی باہمی خط و کتابت مولانا مودودی کی روز اول سے ایکٹو مشاورت کا واضح ثبوت ہیں۔ دارالاسلام ٹرسٹ کے معاملات میں اتنی دور رہتے ہوئے شرکت کے ثبوت میں چوہدری نیاز کے مکتوب نمبر ۲۲ بنام مولانا مودودی مورخہ ۸۔اگست ۱۹۳۷ء قابل توجہ ہے۔ حیات سدید کے صفحہ نمبر ۵۲۲ پر چوہدری نیاز علی خط میں لکھتے ہیں،
’’۳ تاریخ کو حضرت سر علامہ محمد اقبال صاحب کے مکان پر ان کی صدارت میں یہاں ادارہ کے متعلق مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ جرمن نو مسلم علامہ اسد اور سید محمد شاہ کے علاوہ تین چار اور احباب بھی موجود تھے۔ مفصل کارروائی سید محمد شاہ صاحب نے نوٹ کر لی تھی۔ جامعہ ازہر کی چٹھی بعد مناسب ترمیم لکھوا کر بھیج دی گئی ہے اور مولانا اسد، سید محمد شاہ اور جناب (مولانا مودودی) کو ادارہ کا پراسپیکٹس تحریر کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور در اصل سارا کام جناب کی تشریف آوری پر ہی ملتوی ہو رہا ہے۔‘‘
ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ’’حیات سدید‘‘ میں شامل خطوط (جن کی تعداد ڈیڑھ سو ہے) اور چوہدری نیاز علی کے سوانحی حالات کتاب کا اصل ہیں۔ ان کی حیثیت مستند دستاویزات کی ہے۔ بلا شبہہ بہت سے خطوط رسمی نوعیت کے ہیں۔ مکتوب الیہم میں ایسے بھی تھے جو لمبے چوڑے غور فکر کی فرصت نہیں پاتے تھے اور رسمی جملوں پر مشتمل ہیں، مگر بہت سے خطوط زبردست فکری اور علمی مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جناب کے ایم اعظم اس مواد پر ریاضت کرتے۔ اس کی روشنی میں مزید مواد جمع کرتے اور اس پر اپنا ذہن apply کرتے تو اپنے والد محترم کی شخصیت کو کہیں بہتر طور پر پیش کرتے بلکہ ان کے مشن کے تسلسل کی کئی صورتین اختیار کر لیتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک عرش نشین دانشورہیں جو اپنے والد کے دوست اور مہمان، اپنی والدہ اپنے بڑے بھائی، کسی کو معاف نہیں کرتے۔ وہ سب کچھ ادھیڑ دینے میں اپنی دانشوری کی معراج سمجھتے ہیں۔ اس طرح حیات سدید میں بلا شبہہ انتہائی قابل قدر سوانحی مواد موجود ہے، مگر اس مواد کی مدد سے سوانح کی ترتیب کے لیے جو مشقت اور ریاضت ضروری تھی، معلوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف نے اس سے جی چرایا ہے۔ اس سے کتاب کی سوانحی حیثیت سخت مجروح ہوئی ہے۔
لگتا ہے کہ مولانا مودودی اور چوہدری نیاز علی، ہر دو بزرگوں کی اولاد کو اپنے والد کے مشن اور اس کے تسلسل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ چھیانوے سال کی طویل عمر پانے والے بزرگ کی طویل خدمات کو مرتب کرنے والے صاحب پٹڑی سے اتر جائیں تو نقصان کس کا، مصنف کا یاقارئین کا؟ ان کو پٹڑی سے اترنے کے لیے مجید نظامی کے علاوہ اور کئی لوگوں نے خوب تھپکیاں دی ہوں گی۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ کتاب میں غیر متعلقہ مواد کی پوری چھانٹ کی جائے۔ مزید مواد جمع کیا جائے۔ چوہدری نیاز علی کی شخصیت اپنے حقیقی اور دلکش روپ میں پیش کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت صرف کروں، مگر ایسے ستم رسیدگان میں ایک چوہدری نیاز علی ہی تو نہیں۔ آج مولوی تمیز الدین خان کو کون جانتا ہے؟ اگر وہ دستوریہ توڑنے کے حکم کو چیلنج نہ کرتے تو کتب ہاے قانون میں ان کا حوالہ بھی نہ آتا۔ قائد اعظم کے بعد دوسری حیثیت رکھنے والا شخص اپنی تمام تر خدمات اور عظمتوں کے باوجود تاریخ کے صفحات سے بھی غائب رہتا۔ ان کی ایک خود نوشت انگریزی زبان میں چھپی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا اردو ترجمہ فرنٹئیر پوسٹ نے چھاپا تھا جو اب نایاب ہو چکا ہے۔ کیا مجلس کارکنان پاکستان کے روح رواں، مولوی صاحب کی یاد باقی رکھنے کے لیے اسے چھاپنے کی زحمت فرمائیں گے؟ محکمہ آثار قدیمہ کی طرح کوئی ایسا ادارہ قائم ہوسکتا ہے جو تاریخ کے ملبے تلے دبے ہوئے ایسے ہیروں کو دریافت کر کے نئی نسل کے لیے محفوظ کر سکے؟
چوہدری نیاز علی خان واقعتا ہیرے سے کم نہ، تھے مگر جناب کے ایم اعظم صاحب نے ان کی شخصیت کو پیش کرنے میں اگر غیر ذمہ داری نہ بھی کہا جائے تو قلمی نا پختگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بڑی زیادتی ہے۔ mania کسی قسم کا ہو، خاص طور پر چھپنے کا، بڑا خطرناک ہے۔ اگر ہم مصنف کا نفسیاتی جائزہ لیں تو ایک عام عارضے کا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے حقیقی میدان سے نکل کر کسی دوسرے شعبے میں ٹانگ اڑاتا ہے تو پھر اس طرح کی غیر معیاری حرکات سامنے آتی ہیں۔ آج کا دور تو مکمل تخصص کا قیدی ہو گیا ہے۔ قلم کار، ہر کوئی نہیں ہو سکتا ۔ پھر ہر شخص ہر موضوع پر نہیں لکھ سکتا۔ یہ گستاخی ہو گی کہ ہم چوہدری نیاز علی خان کا اس پہلو سے جائزہ لیں۔ ان کا اور سید مودودی کا تقابل کیا جائے تو دونوں میں مشنری ہونے میں کوئی شبہہ نہیں ہو سکتا مگر فرق یہ رہا کہ مولانا آزاد منش تھے، جب کہ نیاز علی صاحب خاں، چوہدری ہونے کے ساتھ ریٹائرڈ افسر تھے۔ وہ افسری سے ریٹائر ہوئے۔ دونوں کے مزاج میں جو فرق ہوتا ہے، وہی چیز ان کے درمیان اختلاف کا باعث ہوئی۔ البتہ یہ ان کا خلوص تھا کہ دونوں نے اس فرق پر قابو پا لیا اور دوبارہ مفاہمت کے ساتھ ہم سفر ہو گئے۔
غیر متعلقہ مواد
حیات سدید میں جو غیر متعلقہ مواد شامل کیا گیا ہے، ان کی جانب کچھ مزید اشارے کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ کتاب میں مولانا امین احسن اصلاحی کا ایک مقالہ شامل کیا گیا ہے۔ کتاب میں یہ مقالہ مکمل طور پر بے جوڑ لگتا ہے۔ اصلاحی صاحب کے مقالے کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا ہے، مگر اس کتاب میں اس کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ ان کے طویل مضمون میں سوانح نیاز کے حوالے سے ایک جملہ بھی نہیں۔ اسی طرح کتاب میں جماعت اسلامی کی حکمت عملی پر ڈاکٹر اسرار احمد، وحیدالدین خان، ارشاد حقانی اور حیدر فاروق مودودی کی تحریریں شامل کی گئی ہیں۔ کتاب تو ’’حیات سدید‘‘ ہے، اس میں جماعت اسلامی کی حکمت عملی کیسے در آئی؟ مولانا مودودی کا علم کلام پر بھی بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ باقاعدہ دو باب باندھ کر مصنف نے اپنے رشحات فکر پیش کیے ہیں۔ اسی طرح جناب الطاف گوہر کے مضامین بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس طرح ایک سوانحی کتاب کو شخصیاتی، جماعتی اور فکری مناقشوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اس غلط مبحث سے کتاب کی سوانحی حیثیت شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں مصنف جو کچھ چاہیں کہہ اور لکھ سکتے ہیں، مگر یہ امر سمجھ سے بالا تر ہے کہ اپنے والد محترم کی سوانح لکھنے بیٹھیں تو جماعت اور مولانا مودودی کی شخصیت کو رگیدنے کا کیا منشا ہو سکتا ہے۔ ہم مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، البتہ کتاب پر لکھتے ہوئے یہ ضرور کہیں گے کہ اس کتاب میں سے کم از کم اک سو بیس صفحات نکال کر، موجودہ کتاب کو کسی حد تک، سوانحی دائرے کے اندر لانا ممکن ہو گا۔
جماعت پر تنقید لکھنا کوئی جرم نہیں۔ جماعت کے اندر اور باہر اسے کبھی جرم نہیں سمجھا گیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ جماعت کے اندر اور باہر تنقید اور احتساب کی جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کسی اور جماعت میں اس کا شائبہ بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت کی پوری ایک تاریخ ہے۔ میں نے تو پہلے بھی لکھا ہے کہ جماعت کی تاریخ کا اسی طرح جائزہ لیا جانا ضروری ہے جس طرح مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے خلافت و ملوکیت میں مسلمانوں کی ہزار سال کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے۔ یہ جماعت کی اپنی بھی ضرورت ہے۔ جماعت کو خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرا کرے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، مگر چوہدری نیاز علی خان کی سوانح کی آڑ میں جماعت اور مولانا پر سنگ زنی کی گنجائش مجید نظامی پیدا کر لیں تو وہ اس کے مجاز ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔مجید نظامی خوش ہوں گے، مگر چوہدری نیاز علی خان کے حقیقی قدر دان بد مزگی کا شکار ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چوہدری نیاز علی خان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ ان کی فکر کو پھیلایا جائے۔ ان کے عمل کو زندہ رکھا جائے۔ ان کے فکری، علمی اور طبعی اثاثوں کی حفاظت کی جائے۔ ان اثاثوں کو جماعت کے تنقیدی جائزہ کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو یہ خدمت ہو گی۔ جماعت کا ایک وسیع حلقہ جماعت کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہے۔ وہ تنقیدی جائزے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ جماعت کے ہاں ایسے کام کو علمی سطح پر انجام دینے کا کوئی موقع نظر نہیں آتا۔ نئے حالات میں اگر چوہدری نیاز علی اور مولانا مودودی کی اولاد اس پہلو ہی سے باقاعدہ کوئی علمی اور سنجیدہ کام کرنا چاہیں تو اس کی پوری گنجائش ہو گی۔ یہ کام مولانا اور چوہدری صاحب ہی کا کام متصور ہو گا۔
باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر از بر ہو
پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو
اس پہلو سے جنابِ خرم مراد کا فکری کام بڑا ہی قابل قدر ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:
’’ہمارے ہاں دنیا بھر کی خرابیوں اور غلطیوں پر قرار دادیں مل جائیں گی، اپنی خرابیوں اور غلطیوں پر کوئی قرار داد نہیں ملے گی۔
ہمارا خیال ہے کہ پبلک میں اور پبلک کے لیے کام کرنے والی جماعتوں کو پبلک کے سامنے ہی اپنااحتساب کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کی تاویل یا پردہ پوشی کے بجائے ان کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی اصلاحی تدابیر کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ اس سے ان کی عزت، دلوں میں مقام اور ان کے دائرہ اثر و حمایت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہو گا۔ صحت مند اور مفید روایات قائم ہوں گی۔رگوں میں نیا خون دوڑے گا اور اصلاح کے دروازے کھلیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ غلبہ دین کی جد و جہد کے مختلف پہلوؤں پر جائزے، غور و خوض، نظر ثانی، تجدید یا تغیر کا عمل شروع ہو جائے گا تو نصف صدی سے زائد کی محنت سے جو پھل ہم نے جمع کیے ہیں، وہ گلنے اور ضائع جانے کے بجائے برگ و بار لائیں گے۔ قوموں اور جماعتوں کے لیے انحطاط، زوال اور بگاڑ مقدر نہیں، نہ جمود اور تعطل۔ اجتہاد و جہاد سے قوت اور شباب کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ماشا ء اللہ ولا قوۃ الا بااللہ۔‘‘ (تحریک اسلامی اہداف، مسائل، حل صفحہ نمبر ۳۱۳)
پاکستانی دارالاسلام .....زبوں حالی
کتاب میں دارالاسلام کے پاکستانی ایڈیشن میں تازہ صورت حال کا مصنف نے بڑی بے چارگی کے انداز سے ذکر کیا ہے۔ حیات سدید کے صفحہ نمبر ۳۴۱، ۳۴۲پر مولف نہایت حسرت سے تحریر فرماتے ہیں:
’’چوہدری نیاز علی خان کی قبر دارالاسلام کی مسجد کے ایک حجرے میں بنائی گئی تھی، مگر میرے برادرِ بزرگ نے جب مسجد کی توسیع کے لیے سعودی گرانٹ قبول کی تو چوہدری صاحب کی قبر مسجد کے صحن میں گم کردی گئی کیونکہ کسی قبر کا مسجد میں ہونا سعودیوں کے لیے شاید قابل قبول نہ تھا۔ مسجد کے داخلی دروازے پر پھولوں کی دو کیاریاں بنا دی گئی ہیں اور دائیں طرف کی کیاری کے نیچے چوہدری نیاز علی خان کی قبر کو چھپا دیا گیا ہے۔ دارالسلام ٹرسٹ جوہر آباد کی دو سو ایکڑ اراضی تو میرے بھتیجے، چوہدری محمد اسلم خان کے فرزند ارجمند چوہدری محمد افضل خاں کے قبضہ میں ہے جب کہ ٹرسٹ کی عمارات جماعت اسلامی کے تصرف میں ہیں جہاں پر وہ ایک ہائی سکول چلا رہے ہیں۔ حالانکہ چوہدری محمد اسلم خان جماعت اسلامی کو پسند نہ کرتے تھے، مگر انہوں نے دارالاسلام کا قبضہ اسی جماعت کے حوالے کر دیا۔ چوہدری نیاز علی خاں تو یہ کبھی نہ چاہتے تھے کہ دارالاسلام بس ایک مدرسے کا ہو کر رہ جائے۔‘‘
چوہدری نیاز علی خاں کے ساتھ جو ان کی اپنی ہی اولاد نے کیا ہے، اس پر آدمی خون کے آنسو نہ روئے تو کیا کرے؟ یہی احوال ’’قرآن سوسائٹی‘‘ کا بھی ہے جو چوہدری صاحب نے اپنا وسیع اثر و رسوخ استعمال کر کے بنائی تھی اور حکومت پنجاب نے اس کے لیے آٹھ مربع اراضی جوہر آباد میں وقف کی تھی۔ اس سوسائٹی کے کئی نامور جج صاحبان ٹرسٹیز تھے۔ چوہدری صاحب کی وفات کے بعد اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں اور زمین کی آمدن کو کوئی بڑی سہولت کے ساتھ خرد برد کر رہا ہے۔ میں اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس واردات کا نوٹس suo moto لیں۔‘‘
چوہدری نیاز کی اولاد نے اپنے عظیم باپ اور ٹرسٹ کے اثاثوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مولف کے تمام گلے شکوے اپنے تایا اور تایا زاد سے ہیں، لیکن وہ خود بھی اپنے طرز عمل پر ذرا غور تو کریں۔ وہ خود اگر اس ٹرسٹ میں ٹرسٹی نہ بھی ہوں تو بھی دس بیس روپے کے کنٹری بیوٹر تو ہوں گے۔ اس طرح وہ موجودہ کتاب تالیف کرنے سے پہلے حساب فہمید کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ اس کے لیے ان کو صرف ایڈووکیٹ جنرل کی اجازت کی ضرورت تھی۔ یہ اجازت ان کو معمولی کوشش سے مل جاتی۔ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے اثر رسوخ کے استعمال کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ در اصل مصنف اپنی اس بے بسی کا غصہ دوسروں پر اتارنے کے درپئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس غرض کے لیے اس کتاب کو اپنے عظیم والد کی شخصیت اور خدمات تک محدود رکھنے کے بجائے لا یعنی مباحث میں الجھ گئے ہیں۔ وہ اپنے والد کے نظریاتی اور دیگر اثاثوں کے تحفظ کی اپنے میں شاید صلاحیت محسوس نہیں کرتے۔
کتاب کو مرتب کرتے ہوئے اسے بڑی ضخامت دینے کے لیے اپنے پر کار قلم سے خوب کام لیا ہے۔ آئیے ہم اب ان مباحث کی طرف بھی کچھ توجہ دیں۔
کتاب کے مولف جناب کے ایم اعظم لکھتے ہیں کہ ان کے والد (جناب چوہدری نیاز علی خان) مولانا مودودی کو دارالاسلام لے کر آئے۔ مولانا مودودی ان کے والد کے پر خلوص دعوت پر حیدرآباد دکن اور دہلی میں اپنے جملہ اثاثہ جات اور کاروبار ترک کر کے آئے۔ ماہنامہ ترجمان القرآن کی اشاعت بھی حیدرآباد سے دارالاسلام منتقل ہوگئی (تو گویا مولانا اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئے تھے)۔ ابتدا ہی میں دونوں پر واضح ہو گیا کہ ان کے ایجنڈے مختلف ہیں، لہٰذا مولانا لاہور چلے گئے۔ اس کے باوجود چوہدری نیاز نے مولانا کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کو جلد ہی واپس لے آئے جہاں تقسیم ہند تک دونوں اکٹھے رہے۔ مولف نے خود بھی لکھا کہ ان کے والد نے اس پر کچھ کہنے سے ہمیشہ گریز کیا۔ مولانا مودودی نے بھی اپنی عادت کے مطابق انتہائی شائستہ خاموشی اختیار کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بزرگوں کے اس پر وقار طرزعمل کے اعتراف اور اظہار کے بعد مولف نے کیا کیا؟ یہ کتاب کا چونکا دینے والا پہلو ہے۔ جماعت اور مولانا مودودی پر تنقید جرم ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے پرہیز کی ہے۔ البتہ جناب کے ایم اعظم صاحب نے جناب مجید نظامی کی تھپکی کے ساتھ، اپنے والد محترم کی شخصیت و خدمات اور سوانح پیش کرتے ہوئے، زیر ترتیب کتاب سے تجاوز کی روش اختیار کی ہے، اسے چیک کرنا ہمارے پیش نظر ہے۔
بنیادی سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ مولانا مودودی کو دارالاسلام پٹھانکوٹ منتقلی کی دعوت علامہ اقبال کی تجویز تھی یا چوہدری نیاز علی کی۔ مولانا مودودی اور اقبال کے ما بین قرب کس سطح کا تھا۔ کیا ان کی باہم ملاقات اور مراسلت کا کوئی وجود ہے یا یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے نزدیک اس بارے میں معتبر ترین شہادت جناب نیاز علی خان اور اقبال کی ہو سکتی ہے۔ ہم سب سے زیادہ اہم اسی کو سمجھیں گے۔ اس قصے میں جناب غلام احمد پرویز نے جو نئی کہانی پیش کرنے کی کوشش کی ہے اسے نظر انداز کرنے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر شروع میں دے چکے ہیں۔
جناب نیاز علی خان، مولا نا مودودی اور سید نذیر نیازی کے خطوط سے یہ امر ثابت ہے کہ مولا نا مودودی کی علامہ اقبال سے ملاقات بہر حال موعودہ تھی۔ حیات سدید کے صفحہ نمبر ۵۲۱ پر نیاز علی خان کے مولانا مودودی کے نام خط نمبر ۲۱ مورخہ ۱۸۔ جولائی ۱۹۳۷ء میں یہ لکھا ہے کہ
’’پھر علامہ اقبال سے مل کر آپ کی پوری اسکیم ان سے بیان کی جائے گی۔ وہ اس کی سرپرستی کے لئے بالکل آمادہ ہیں۔‘ ‘
اسی طرح صفحہ نمبر ۵۲۷ پر درج نیاز علی خان کے خط نمبر ۲۶ میں یہ الفاظ موجود ہیں :
’’ہم دونوں ۱۰۔اکتوبر کو صبح کی گاڑی سے دہلی پہنچ جائیں گے۔ مجلس سے فارغ ہوتے ہی آپ کو ہمارے ساتھ جمال پور تشریف لانا ہو گا۔ اس جگہ اسد صاحب اور مولانا قرشی صاحب کو بلا لیا جائے گا۔ یہاں سے فارغ ہو کر سب لاہور سر محمد اقبال صاحب کی خدمت میں چلیں گے۔ ‘‘
مولانا مودودی کے نام سید نذیر نیازی کا مشہور و معروف مکتوب مورخہ ۱۸۔ اپریل ۱۹۳۸ء درج ذیل ہے:
’’مکرمی۔ السلام علیکم۔
امید ہے آپ بفضلہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دن ہوئے سید محمد شاہ صاحب سے معلوم ہوا تھا کہ آپ جمال پور تشریف لے آئے ہیں اور عنقریب لاہور بھی آئیں گے۔ اس وقت سے برابر آپ کا انتظار ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ارادہ فی الواقعہ لاہور آنے کا ہے تو جلدی تشریف لائیے تاکہ ملاقات ہو جائے۔ اپنی طرف سے یہ گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی حالت نہایت اندیش ناک ہے۔ ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں مگر اس بات کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھئیے گا۔ کسی سے ذکر نہ کیجئیے گا۔ لہذابہتر یہی ہو گا کہ آپ جس قدر ہو سکے جلدی تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لئے دعا فرمائیے ۔ ‘‘
اس کے علاوہ سید نذیر نیازی اپنی کتاب مجلس اقبال اوراق گم شدہ کے صفحہ نمبر ۸۵۔۸۶ پر روایت کرتے ہیں:
’’چوہدری نیاز علی خان جاوید منزل میو روڈ لاہور تشریف لائے اور ان کے ہمراہ علامہ محمد اسد بھی تھے۔ چوہدری صاحب نے حضرت علامہ کی مزاج پرسی کے بعد عرض کیا کہ انہوں نے جمال پور میں ایک وقف ’’دارالاسلام ‘‘کے نام سے قائم کیا ہے تاکہ وہاں مسلمانوں کی اصلاح و تربیت اور دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ حضرت علامہ اس کام میں ان کی رہنمائی فرمائیں اور جیسا ان کا مشورہ ہو، اس کے مطابق بعض علمائے دین کو دارالاسلام آنے کی دعوت دی جائے۔ حضرت علامہ نے کہا، سر دست ایک نام میرے ذہن میں آتا ہے۔ حیدرآباد دکن سے ’’ترجمان القرآن ‘‘ نام سے ایک بڑا اچھا رسالہ نکل رہا ہے۔ مودودی صاحب اس کے ایڈیٹر ہیں۔ میں نے ان کے مضامین پڑھے ہیں۔ دین کے ساتھ ساتھ وہ مسائل حاضرہ پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب ’’الجہاد فی الاسلام‘‘ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ آپ کیوں نہ انہیں دارالاسلام آنے کی دعوت دیں، میرا خیال ہے کہ وہ دعوت قبول کر لیں گے۔‘‘
یہاں ہم حیات سدید کے مصنف کے والد محترم جناب چوہدری نیاز علی خان کے ایک مضمون کا حوالہ بھی دینا چاہیں گے۔ یہ مضمون دارالاسلام سے شائع ہونے والے جریدہ جس کانام بھی دارالاسلام ہی تھا اس کے ستمبر ۱۹۳۹ء کے شمارے میں چوہدری صاحب کے حوالے سے تحریر ہے:
’’اس دوران میں مجھے مولانا سید ابوالاعلی مودودی کے ساتھ اس ادارے کے متعلق خط و کتابت کا موقع ملا اور حضرت علامہ کی نظر جوہر شناس بھی سید صاحب پر جا پڑی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حیدرآباد سے یہاں کا موقع و محل دیکھنے آئے اور حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تین صحبتوں میں ان سے مفصل گفتگو کرنے کے بعد اس ادارے میں جس کا نام خود انہوں نے دارالاسلام تجویز کیا‘ نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔‘‘
ان حوالوں کے علاوہ جناب غلام احمد پرویز کے ہمدم دیرینہ جناب شیخ سراج الحق کا ایک خط حیات سدید کے صفحہ ۱۹۱ پر درج دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ۱۹۲۔۱۹۳ پر خط مورخہ ۴؍جولائی ۱۹۷۶ء میں یہ درج ذیل تفصیل موجود ہے:
’’علامہ اقبال نے دارالاسلام کا ایک تصور پیش کیا تھا اور خان صاحب چوہدری نیاز علی خان مرحوم نے اس تصور کوعملی شکل دینے کے لیے اپنی جائداد کا ایک معتد بہ حصہ وقف کر دیا تھا۔علامہ اقبال کا ارادہ خود وہاں منتقل ہوجانے کا تھا، لیکن بد قسمتی سے وہ شدید بیمار ہو گئے۔ اس پر یہ طے پایا کہ سر دست وہاں کسی مناسب شخص کو بلا لیا جائے جو دارالاسلام کے ابتدائی مراحل طے کرنے میں مدد دے۔ دیگر ممالک سے سکالرز بلانے کے لیے بھی علامہ اقبال کی طرف سے خط و کتابت ہو رہی تھی۔ پہلے تجویز ہوا کہ خود پریز صاحب ملازمت چھوڑ کر دارالاسلام منتقل ہو جائیں، لیکن قائد اعظم اس سے متفق نہ ہوئے کہ چوہدری صاحب ملازمت چھوڑ دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ چوہدری صاحب دہلی میں ان کے قریب رہیں۔ چنانچہ اس پر طے پایا کہ دارالاسلام کے لیے مودودی صاحب کو بلا لیا جائے۔ چوہدری نیاز علی صاحب نے اس تجویزسے اتفاق کیا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، نیاز علی خان صاحب مرحوم نے علامہ اقبال کی اجازت سے مودودی صاحب کو دعوت نامہ بھیجا تھا۔ ‘‘
مولانا مودودی سے علامہ کی ایک ملاقات کی گفتگو کا کچھ حصہ، ہارون رشید نے اس طور پر نقل کیا ہے:
’’لاہور میں وہ اقبال سے ملے اور دارالاسلام کے منصوبے پر اتفاق رائے ہو چکا تو ان سے (مولانا مودودی نے) عرض کیا: ’’میری ایک بات مان لیجیے، سر کا خطاب واپس کر دیجیے کہ یہ آپ کو جچتا نہیں۔ ‘‘بعد میں ایک ذاتی دوست کو ابوالاعلیٰ نے بتایا کہ یہ بات سن کر اقبال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ سید کو ملال ہو اکہ انہوں نے اقبال کو رنجیدہ کر دیا ہے۔‘‘ (ترجمان القرآن اشاعت خاص، مئی ۲۰۰۴ء صفحہ نمبر ۱۲۸)
ان کثیر، معتبر اور ٹھوس شواہد کی بنا پر یہ تو آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ واضح ہے کہ ہر جانب سے مایوسی کے بعد، مولانا مودودی کو آخر کار دارالاسلام آنے کی تجویز علامہ اقبال کی تھی۔ چوہدری نیاز علی خان نے اس تجویز سے اتفاق کے بعد اسے بروئے کار لانے کے لیے موثر طور پر pursue کیا۔ علامہ اقبال اور مولانا مودودی کے مابین مراسلت اور ملاقات بھی ثابت شدہ معلوم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے مولانا کے نام خطوط تو ہجرت کے دوران محفوظ نہ رہ سکے مگر مولانا کے علامہ کے نام چار خطوط سید نذیر نیازی سے مہیا ہوئے اور ان کو وثائق مودودی میں محفوظ کیا گیا ہے۔ بطور ثبوت ان خطوط کو آخر پر شامل کیا جاتا ہے۔ یہ امر بھی انتہائی اہم ہے کہ مولانا مودودی کے سوا کوئی اس کارِ خیر کے لیے نقل مکانی کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ حیات سدید کا سب سے اہم پہلو یہی تھا، مگر مصنف نے اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی بلکہ اس کی پوری بے قدری فرمائی۔
(جاری)
شاتم رسول کی توبہ کا شرعی حکم
امام تقی الدین السبکی الشافعیؒ
(۹ ویں صدی ہجری کے ممتاز شافعی فقیہ اور مجتہد علامہ تقی الدین السبکیؒ نے اپنی معروف تصنیف ’’السیف المسلول علیٰ شاتم الرسول‘‘ کی ایک مستقل فصل میں اس مسئلے پر مفصل کلام کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو تو ا س کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں۔ امام صاحب نے ایسے شخص کی توبہ قبول کرنے کے حق میں قرآن وسنت سے مثبت طور پر بھی دلائل پیش کیے ہیں اور اس ضمن میں پیش کیے جانے والے اشکالات کا بھی عالمانہ تجزیہ کیا ہے۔ توہین رسالت کی سزا کے حوالے سے جاری مباحثہ کے تناظر میں، یہاں امام سبکی کی اس بحث کے بعض اہم اور نسبتاً عام فہم اجزا کی تلخیص پیش کی جا رہی ہے۔ عمار ناصر)
توبہ کی قبولیت کے حق میں دلائل
ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنے کے حق میں ہمارے دلائل حسب ذیل ہیں:
۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
قُل لِلَّذِیْنَ کَفَرُواْ إِن یَنتَہُواْ یُغَفَرْ لَہُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّۃُ الأَوَّلِیْنِ (الانفال: ۳۸)
’’کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اگر دوبارہ یہ راستہ اختیار کریں گے تو ان سے پہلے ایسے لوگوں کا انجام گزر چکا ہے۔‘‘
نیز ارشاد ہے:
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنفُسِہِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَۃِ اللّٰہِ، إِنَّ اللّٰہَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیْعاً، إِنَّہُ ہُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ (الزمر: ۵۳)
’’کہہ دو کہ اے میرے بندو جنھوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ بے شک وہ بخش دینے والا، بے حد مہربان ہے۔‘‘
نیز فرمایا:
أُوْلَئَکَ جَزَآؤُہُمْ أَنَّ عَلَیْْہِمْ لَعْنَۃَ اللّٰہِ وَالْمَلآئِکَۃِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِیْنَ، خَالِدِیْنَ فِیْہَا، لاَ یُخَفَّفُ عَنْہُمُ الْعَذَابُ وَلاَ ہُمْ یُنظَرُونَ، إِلاَّ الَّذِیْنَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّٰہَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ (آل عمران: ۸۷۔۸۹)
’’ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں، سب کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انھیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔‘‘
یہ آیات مرتد کی توبہ قبول کرنے کے معاملے میں نص ہیں اور سب وشتم کی وجہ سے مرتد قرار پانے والا بھی ان کے عموم میں داخل ہے۔
۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:
فَإِن یَتُوبُوا یَکُ خَیْْراً لَّہُمْ وَإِن یَتَوَلَّوْا یُعَذِّبْہُمُ اللّٰہُ عَذَاباً أَلِیْماً فِیْ الدُّنْیَا وَالآخِرَۃِ وَمَا لَہُمْ فِیْ الأَرْضِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیْرٍ (التوبہ: ۷۴)
’’اب اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور اگر واپس پلٹ جائیں تو اللہ انھیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین میں انھیں نہ کوئی دوست میسر ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔‘‘
یہ آیت رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے غزوۂ تبوک کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ’’ہماری اور محمد کی مثال (نعوذ باللہ) وہی ہے جو اس مقولے میں بیان کی گئی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ وہ تمھیں ہی کھا جائے۔ اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔‘‘ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ان منافقین کے بارے میں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ انھیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول ہے اور اس کی وجہ سے ان سے دنیا اور آخرت کی سزا ٹال دی جائے گی۔
۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :
’’الاسلام یجب ما کان قبلہ‘‘۔
’’اسلام ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے ہوں۔‘‘
یہ بات آپ نے ہبار بن الاسود بن عبد المطلب کے بارے میں فرمائی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں قتل کا حکم دے رکھا تھا، لیکن اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں آپ کو برا بھلا کہنے اور ایذا دینے میں حد سے تجاوز کر گیا تھا، لیکن آپ مجھ سے درگزر فرمائیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ’’قد عفوت عنک والاسلام یجب ما کان قبلہ‘‘۔ (میں نے تمھیں معاف کر دیا اور اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے)۔ اس ارشاد کی رو سے قبول اسلام کے بعد آدمی کا وہ جرم بھی معاف ہو جائے گا جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے ہو، کیونکہ آپ نے خود ایسے شخص کے قبول اسلام کے بعد اپنے حق کو معاف کر دیا ہے۔ گویا آپ کے اس ارشاد کی یوں تعبیر کی جا سکتی ہے کہ ’’جو شخص اسلام قبول کر لے، میں نے اسے معاف کر دیا۔‘‘
۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
لا یحل دم امرئ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ الا باحدی ثلاث: الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعۃ۔
’’جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کو تین صورتوں کے علاوہ قتل کرنا جائز نہیں۔ ایک شادی شدہ زانی، دوسرا جسے قصاص میں قتل کیا جائے اور تیسرا وہ جو دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔‘‘
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ جرائم کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں اور چونکہ گستاخی کا مرتکب دوبارہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس زمرے میں نہیں آتا، اس لیے اس کو قتل کرنا بھی جائز نہیں۔
۵۔ سب وشتم کے بعد توبہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے اور معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مخصوص دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اب اگر یہ مانا جائے کہ (سب وشتم کے بعد توبہ کر کے) حالت اسلام میں مرنے والے کے ذمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق باقی ہے، کیونکہ دنیا میں اسے اس کی سزا نہیں دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو جب تک آپ خود قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت حال پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے کہ آپ کی امت کے کسی فرد کے جنت میں جانے میں کسی دوسرے آدمی کے حق کی وجہ سے، چہ جائیکہ خود آپ کے حق کی وجہ سے، تاخیر ہو جائے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بعد اپنی امت کے ایسے تمام افراد پر اپنے حق کے تحت لازم ہونے والی سزا کو آپ معاف فرما چکے ہیں)۔
مزید برآں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے پر قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی توبہ قبول کی جائے، کیونکہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور قتل کی سزا اس سے ساقط ہو جائے گی۔
توبہ کی قبولیت پر اشکال کا جواب
یہ اشکال پیش کیا جا سکتا ہے کہ سب وشتم حق اللہ نہیں، بلکہ حق العبد ہے اور حق العبد توبہ سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ خود موجود نہیں جبکہ کسی دوسرے کو آپ کا یہ حق معاف کرنے کا اختیار نہیں تو آپ کا حق کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ یہ حق العبد ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رافت ورحمت اور شفقت کی وجہ سے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ ہاں اگر اللہ کی قائم کردہ حرمتیں پامال کی جاتیں تو آپ ان کا انتقال لیتے تھے۔ سب وشتم کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے نبیوں کو برا بھلا کہہ کر دراصل اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اس لیے اگر وہ سب وشتم کے بعد اپنے کفر پر قائم رہے تو اس پر قتل کی سزا لازم ہوگی، لیکن توبہ کر کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں حق اللہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا تعلق ہے تو جب آپ نے خود اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا تو آپ کی وفات کے بعد کیسے آپ کی ذات کے لیے انتقام لیا جا سکتا ہے؟ دراصل اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کو حق اللہ کے تابع کر دیا ہے، اس لیے جب اصل یعنی حق اللہ ساقط ہوگا تو اس کے تحت حق العبد بھی ساقط ہو جائے گا۔
اس پر اتفاق ہے کہ حق اللہ کے طو رپر شاتم رسول کو قتل کرنا لازم نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے معاف کرنے کا حق تھا، اسی لیے آپ نے ابو سفیان، عبد اللہ بن ابی سرح اور دوسرے بہت سے ایسے افراد کو معاف کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کو قتل نہیں کیا۔ اگر شاتم رسول کو حق اللہ کے طور پر قتل کرنا لازم ہوتا تو آپ ان لوگوں کے قبول اسلام کے بعد بھی اس کو ترک نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص کو قتل کرنا دراصل حق اللہ کے طو رپر تھا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو آپ انتقام لیتے ہی نہیں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ظرفی سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے اور امت پر ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والے تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے گستاخ کو معاف کرنے پر راضی ہیں، چنانچہ شاتم رسول کے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں اگر اسے معاف کیا جائے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہوگی۔
اصل یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنی کسی گستاخانہ بات سے) غصہ دلائے، آپ کو اسے قتل کرنے کا اختیار تھا۔ اب یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک آپ کی ناراضی برقرار ہو۔ جب آپ (توبہ کی وجہ سے) اس شخص سے راضی ہو گئے تو قتل کا حکم بھی خود بخود زائل ہو گیا۔ گویا قتل کا مدار سب وشتم پر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی پر ہے۔ جہاں آپ کی ناراضی موجود ہوگی، وہاں قتل کرنا جائز ہوگا اور جہاں ناراضی ختم ہو جائے گی، وہاں قتل کی سزا بھی باقی نہیں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو راضی کیا جاتا تو آپ راضی ہو جاتے تھے۔ جب آپ کو سب وشتم کرنے والا دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا مورد نہیں رہتا تو اسے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟
یہ اشکال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ’’من سب نبیا فاقتلوہ‘‘۔ (جو شخص کسی نبی کو برا بھلا کہے، اس کو قتل کر دو)۔ یہ ارشاد ایسے شخص کے مستوجب قتل ہونے کے لیے کافی ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ’’من بدل دینہ فاقتلوہ‘‘۔ (جو شخص اپنا دین بدل لے، اس کو قتل کر دو) ظاہر ہے کہ اس سے یہ استدلال درست نہیں کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ’’من سب نبیا فاقتلوہ‘‘ کو بھی توبہ کے قابل قبول نہ ہونے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔
حاصل کلام یہ ہے کہ سب وشتم کا مرتکب کی توبہ میں اگر ایسے قرائن پائے جائیں جو شک وشبہے کا موجب ہوں اور وہ خبث باطن سے متہم ہو تو ایسے شخص کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں تو اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن قوی بات یہی ہے کہ اس کے اسلام کو قبول کر لیا جائے او ر قتل کی سزا ٹال دی جائے، جبکہ اگر توبہ کرنے والے کی حسن نیت کے آثار اور قرائن ظاہر ہوں تو میرے نزدیک اس کی توبہ کو قبول کرنا اور اس سے قتل کی سزا کو ٹال دینا قطعی طور پر لازم ہے۔ ایسے شخص کو قتل کرنے پر اصرار کرنا ایسا جمود ہے جس کی بنیاد کسی صریح، واضح اور قوی دلیل پر نہیں، بلکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر اسے قتل کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں باز پرس فرمائیں گے۔
شاتم رسول کی توبہ ۔ سعودیہ کے سابق مفتی اعظم الشیخ عبد العزیز بن بازؒ کا فتویٰ
ادارہ
فاذا کان من سب الرب سبحانہ او سب الدین ینتسب للاسلام فانہ یکون مرتدا بذلک عن الاسلام ویکون کافرا یستتاب فان تاب والا قتل من جہۃ ولی امر البلد بواسطۃ المحکمۃ الشرعیۃ وقال بعض اہل العلم انہ لا یستتاب بل یقتل لان جریمتہ عظیمۃ ولکن الارجح ان یستتاب لعل اللہ تعالی یمن علیہ بالہدایۃ فیلزم الحق ولکن ینبغی ان یعزر بالجلد والسجن حتی لا یعود لمثل ہذہ الجریمۃ العظیمۃ وہکذا لو سب القرآن او سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او غیرہ من الانبیاء فانہ یستتاب فان تاب والا قتل
(http://www.binbaz.org.sa/mat/354)
’’ذات باری یا دین کو برا بھلا کہنے والا اگر مسلمان ہو تو ایسا کرنے سے وہ اسلام سے مرتد اور کافر قرار پائے گا اور اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے تو درست، ورنہ حاکم شہر شرعی عدالت کی وساطت سے اس پر قتل کی سزا نافذ کر دے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایسے شخص کو توبہ کے لیے نہ کہا جائے بلکہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کا جرم بہت سنگین ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز فرمائیں اور وہ حق پر پختگی سے قائم ہو جائے، البتہ اسے کوڑوں اور قیدکی صورت میں تعزیری سزا دی جانی چاہیے تاکہ وہ آئندہ کبھی اس جرم عظیم کا ارتکاب نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے تو درست، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔‘‘
مشہورات کو مسلمات بنانے سے اجتناب کی ضرورت
مولانا محمد عبد اللہ شارق
میرے خیال میں اب وہ وقت آگیا ہے کہ میرے ایسے طالبِ علم کو توہین رسالت کی سزا پر جاری مباحثہ کے ضمن میں کچھ عرض کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جناب مولانا زاہدالرشدی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بہت طویل انتظارکے بعد ہی سہی، بہرحال اِس نازک اور حساس مسئلہ میں خاموشی پر اظہار کو ترجیح دی، بغیر کسی لگی لپٹی کے حنفی نکتۂ نظر کو وضاحت سے بیان کیا اور کسی کے طعن وملامت کی پروا کیے بغیر پڑھنے لکھنے والے بچوں کے اس کرب کا مداواکیا جو اِ س مسئلہ کی بابت پیدا ہونے والے سنجیدہ ابہامات اور ان پربڑوں کی لامتناہی خاموشی کو دیکھ کر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اِس جرا تِ اظہار کی امید مولاناکی شخصیت سے ہی تھی جسے انہوں نے اپنے مخصوص طرزِمتانت اور اعتدال کے ساتھ خوب نبھایا۔
اِس مسئلے کے حوالہ سے میرے ایسے نو آموزوں کا کرب یہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں اس مسئلہ میں فقہِ حنفی کے نکتۂ نظر کونظر انداز کیا جارہا ہے یا امام ابوحنیفہ ؒ کے مقلدین اِ س مسئلہ میں ان کی تقلید سے انحراف کررہے ہیں یا پھر زیادہ قابل قبول لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ اِ س مسئلہ کے اندر حنفی نکتۂ نظر کی تشریح اور ترجمانی کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی نے جو موقف اختیار کیا ہے، اس سے اختلاف کیا جار ہا ہے۔ نہیں، ہماری نظر میں یہ قطعاً کوئی تشویش اور اضطراب کی بات نہیں۔ علامہ شامی کی حیثیت فقہِ حنفی کے ایک محقق اور شارح کی ہے۔ اگر ہمارے ہاں اکثر وبیشتر مسائل میں ان کی تحقیق اور ترجیح پر اعتماد کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب مسائل میں ان ہی کی رائے کو حرفِ آخر قرار دیا جائے۔ فتاویٰ شامی کے کتنے ہی مندرجات ایسے ہیں جن سے ہمارے ہاں کے جمہور علما اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ان میں ایک مسئلہ توہین رسالت کی سزا کا بھی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہرمسئلہ میں علامہ شامی کی تحقیق پر ہی عمل کرنا یقیناکوئی شرعی فریضہ نہیں۔ پھر اس مسئلہ کے اندر حنفی نکتۂ نظر کی تشریح وتعبیر کے ضمن میں بعض دیگر ایسے معتبرنام بھی موجود ہیں جن کی تحقیق علامہ شامی کی رائے کے برخلاف ہے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ کی طرف وہ موقف منسو ب کیا ہے جس کے قائل پاکستان کے جمہور اہل علم ہیں۔ ان میں سے بہت سے حضرات کے اسماے گرامی علامہ خلیل الرحمن قادری نے اپنے مضمون (مطبوعہ : محدث؍ شمارہ اگست ۲۰۱۱ء) میں بڑی جانفشانی سے ضبط کردیے ہیں۔ اگر ہمارے جمہور علما اس مسئلہ کی حنفی تنقیح میں علامہ شامی کی ترجمانی کی بجائے دیگر علما کی تحقیق کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ کوئی پریشان کن صورتِ حال نہیں۔
نیز فرض کیجیے کہ اگر دلائل کو پر کھنے کے بعد یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ اِ س مسئلہ کی حنفی تنقیح کا حق علامہ شامی نے ادا کیا ہے اور امام ابوحنیفہ کا اصل نکتۂ نظر وہی ہے جو علامہ شامی نے بڑی عرق ریزی اور شرح وبسط کے ساتھ بیان کردیا ہے تو بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے اہلِ علم کو اس مسئلہ میں کوئی مختلف نکتۂ نظراختیار کرنے کا حق حاصل نہ ہو۔ اصحابِ فتویٰ (جو حقیقتاً اصحابِ فتویٰ ہیں) اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنے ہی مسائل میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے اما م کی بجائے صاحبین اور بعض مسائل میں یکسر کسی دوسری فقہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآنِ مجید کی تعلیم پر اجرت لینے اور لاپتہ خاوند کی بیوی کے مدتِ انتظار سمیت کئی مسائل کی ایک فہرست ہے جو مرتب کی جاسکتی ہے ۔ ان مسائل میں فقہ حنفی کے ائمہ کی بجائے ہمارے علما کسی اور فقہ کے قول کو اختیار کرتے ہیں ۔ اگر مسئلہ ’’توہین رسالت کی سزا‘‘ کے ضمن میں بھی پاکستان کے حنفی علما اپنے امام کی بجائے کسی دوسری رائے کوترجیح دیں تو یہ کوئی انوکھی اور اپنی نوعیت کی منفردمثال نہیں اور نہ ہی اس پر ہمیں سر پکڑ کر بیٹھ جانے کی ضرورت ہے۔
ہمارے درد اور کرب کا سلسلہ تب شروع ہوا جب ’’تحریک ناموسِ رسالت ‘‘ کے بھر پور حرارت کے دنوں میں ’’توہین رسالت کی شرعی سزا‘‘ کے حوالہ سے مذہبی رسائل وجرائد کے اندر قطار اندر قطار مضامین لگنا شروع ہوئے اور ان کے اندر پاکستان کے جمہور علما کے موقف کو علامہ شامی کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ نہ صرف یہی ، بلکہ علامہ شامی مرحوم کے اِ س مسئلہ پر تحریر کیے گئے مستقل اور منفرد رسالہ ’’تنبیہ الولاۃ والحکام‘‘ اور فتاویٰ شامی کے ’’جلد نمبر‘‘ اور’’ صفحہ نمبر‘‘ کا حوالہ دے دے کر متواتر یہ دعویٰ دہرایا جاتا رہا کہ توہین رسالت کا مرتکب واجب القتل اور ناقابل معافی ہے اور اس کی کسی ذیلی صورت اور کسی فرع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ناطقہ سربگریباں کہ اسے کیا کہیے! فقہِ حنفی کا طالبِ علم جب تحقیق کے نام پر ڈھائے گئے اس ’’ظلم‘‘ کو دیکھتا تو سمجھ نہ پاتا کہ اِسے علمی افلاس کہنا چاہیے یا علمی خیانت؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے جبکہ اِس خطہ کے مسلمانوں میں اِس حوالہ سے خصوصی طور پر بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے۔ اس حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان میں ’’قانون توہین رسالت‘‘ جیسا کوئی قانون ہی مطلوب تھاجس میں لاقانونیت کا دروازہ بند کرنے کے لیے توہین رسالت کے جرم کی انتہائی سے انتہائی سزا مقرر کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شعوری کارکن کی حیثیت سے پورے خلوص کے ساتھ ، میں خود ذاتی طور پر تحریکِ ناموسِ رسالت کے مختلف اجتماعات میں شریک ہوتا رہا جس کا ایجنڈا ’’قانون توہین رسالت ‘‘ کو تعطیل اور ترمیم سے بچانا تھا۔ قائدِ اعظم جیسے آدمی کا اپنے دور میں گستاخِ رسول کے ایک قاتل کا مقدمہ لڑنا اور اب ایک سرکاری اہل کار کے ہاتھوں صوبائی گورنر کے قتل جیسے واقعات بتلاتے ہیں کہ یہ قانون اپنی سخت گیر شکل میں ہی خطہ کے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے اور اس کی فعالیت اور بغیر ترمیم کے برقرار رہنا ہی لوگوں کے جذبات کو قانونی دائرہ کا پابند رکھ سکتا ہے۔ بصورتِ دیگر اِس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ لوگ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں گے، بلکہ اِس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ ممتاز قادری کی طرح لوگ از خود ہی اپنے جذبات کی تشفی کے من پسند راستے تراشنا شروع کردیں گے۔ البتہ علماے کرام کے لیے ضروری ہے کہ اِس حوالہ سے غیر محسوس طریقہ پر عوامی جذبات کی نئی رخ سازی کا فریضہ انجام دیں اور انہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت وعظمت پہ جان دینے کے ساتھ ساتھ دعوتِ دین کے حکیمانہ آداب وضروریات اور تقاضوں سے بھی آگاہ کریں تاکہ عوامی اعتماد کے ساتھ اِس قانون کی درست صورت گری ممکن ہوسکے، جیسا کہ مولانا مفتی محمد زاہد نے لکھا ہے :’’ اہل علم سے یہ درخواست ہے کہ مسئلے کے تمام پہلوؤں کو اور ملک کی معروضی صورتِ حال کو سامنے رکھ کر سنجیدہ غور کا سلسلہ شروع کریں اور بجائے اس کے کہ کوئی موقع دیکھ کر حکومت کوئی لسٹم پسٹم ترمیم لے آئے اور دینی حلقوں کے ساتھ اسی طرح کا ہاتھ ہوجائے جیساکہ ۲۰۰۷ء میں حدود کے مسئلہ پر ہوا تھا، علماء کے لیے مناسب ہوگا کہ مختلف طبقات کے جائز تحفظات کو سامنے رکھ کر از خود قرآن وسنت کی روشنی میں کوئی قانونی پیکج پیش کردیں۔‘‘
تاہم جب تک یہ سب ممکن نہیں ہو پاتا، حالات کے معروضی تناظر، ریاست کے جمہور عوام کے جذبات واحساسات اور مفادِ عامہ کی روشنی میں قانونِ توہین رسالت کا جوں کا توں برقرار رہنا ہی حکمت ودانش کا تقاضا ہے اور اِس صورت میں علامہ شامی کی تحقیق اور توہین رسالت ایکٹ کے مابین بھی ماسوائے ایک نکتہ کے کوئی تصادم موجود نہیں ہے، جبکہ بعض حضرات کی طرف سے اِسے بہت بڑھاچڑھا کر پیش کیا جارہا ہے۔ علامہ شامی کی تحقیق کے مطابق توہین رسالت کا مرتکب خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے خون کی حرمت کھو کر ’’مباح الدم ‘‘ہوچکا ہے اور انہی کے مطابق اس میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ’’مباح الدم ‘‘ کی اصطلاح ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو واجب القتل ہو یا نہ، لیکن اسے قتل کرنا بہر حال جائز ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک گستاخِ رسول اگر مسلم ہو تو مباح الدم کے ساتھ ساتھ وہ واجب القتل بھی ہوچکا ہے، لیکن اگر غیرمسلم ہو تو وہ شرعاً واجب القتل نہیں، بلکہ اس کو قتل کرنا یا قتل سے کم تر سزا دینا قاضی کی تعزیری صواب دید پر منحصر ہے ۔ ’’تعزیراتِ پاکستان‘‘ نے اگر اپنے اسی صواب دیدی اختیار کو عوامی جذبات کے مطابق برمحل استعمال کرتے ہوئے صرف موت کی سزا متعین کردی ہے تو اِس میں فقہِ حنفی کی مخالفت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ البتہ اگر گستاخِ رسول توبہ کرلے تو اس کی معافی ہے یانہیں ؟یہ ایک صورت ہے جس میں فقہِ حنفی اور قانون توہینِ رسالت کے درمیان ہم آہنگی نظر نہیں آتی۔ علامہ شامی کے مطابق توبہ کرلینے سے گستاخِ رسول کے خون کی حرمت واپس لوٹ آئے گی اور اسے قتل کرنا درست نہیں۔
تحریکِ ناموسِ رسالت کی کامیابی کے لیے ا تنا ہی کافی تھا کہ پاکستان کے جمہور اہل علم اور تمام مسالک اس سلسلہ میں یک نکاتی ایجنڈے پر متفق تھے کہ قانون توہین رسالت میں کسی طور ترمیم نہیں ہونے دی جائے گی۔ اگر اِس سلسلہ میں علامہ شامی یا پاکستان کے کسی اور صاحبِ علم کی رائے استثنائی تھی تو اِس سے تحریک کو کیا نقصان تھا؟ ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام جمہور اہلِ علم کی پشت پر کھڑے تھی اور جمہوری حکومت نے اگر فیصلہ جمہور کے حق میں کیا تو یہ جمہور کی قوت کی وجہ سے ممکن ہوا، علامہ شامی مرحوم کا غلط حوالہ استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں۔علامہ شامی ہمارے حکمرانوں کے لیے کوئی بہت محترم شخصیت نہیں کہ ان کانام سن کر وہ چاروں شانے چت گر پڑتے اور اپنے ارادوں سے تائب ہوجاتے۔
علامہ شامی موصوف نے ہی اپنی کتاب ’’شرح عقود رسم المفتی ‘‘ میں ایک مستقل عنوان قائم کرکے بتایا ہے کہ بعض مسائل یوں مشہور ہوجاتے ہیں کہ جیسے یہ متفقہ امور ہیں ، حالانکہ اِس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اِس ضمن میں بطورِمثال انہوں نے ’’ توہین رسالت کی سزا‘‘ کے مسئلہ کا بھی ذکر کیا ہے ۔ ان کی رائے میں ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہوئے صرف متاخرین کی کتابوں کو نہ دیکھے ، بلکہ فقہ کے اصل مآخذ سے بھی رجوع کرے، کیونکہ بعض اوقات کسی مسئلہ کو نقل کرتے ہوئے یا اس کی تشریح کرتے ہوئے کسی عالم سے غلطی ہوجاتی ہے اور آنے والے اسی کو نقل درنقل کرتے چلے جاتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی اجماعی مسئلہ ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ مسئلہ سرے سے تعبیر اور تشریح کی اس غلطی کانتیجہ ہوتا ہے جو پہلے عالم سے ہوئی ۔ اصل ماخذ کے ساتھ مراجعت کرنے سے یہ امر واضح ہوجاتا ہے۔
حاصل یہ ہے کہ ایسے بے شمار مسائل ہیں جن میں تحقیق واختلاف کا باب وسیع ہے ، مگر ان میں کسی ایک قول کی مقبولیت اور شہرتِ عامہ نے عوام کی نظروں میں ہر قسم کی تجدید اور اختلافِ رائے کے دروازے کو مقفل کردیا ہے۔ اگر علماءِ کرام کا کام بھی یہی ہے کہ انہوں نے عوام کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایسے مسائل میں مشہورات کوہی قطعیات کا درجہ دے کر سطحی اندازِ فکر اختیارکرنا ہے تو پھر ہمارے خیال میں انہیں اپنی عمر عزیز کے آٹھ دس سال مدرسہ کی چاردیواری میں خرچ کرنے کی بجائے کسی اور شعبہ میں کارآمد بنانے چاہئیں۔ اس طرزِ فکر کا اظہار کرنے کے لیے اتنے طویل دورانیہ کی ریاضت کا بوجھ اٹھانے کیا ضرورت ہے؟ اگر شہرتِ عامہ کو مسائل کی قطعیت کا سبب فرض کرلیا جائے تو بہت سی لاینحل پیچیدگیاں پیدا ہوجائیں گی۔ علما کافرض بنتا ہے کہ اختلافی مسائل کو اجماعی بنانے اور ان میں غیر ضروری شدت اختیار کرنے سے اجتناب کریں، بلکہ ایسے مسائل میں عوامی رویوں کو اعتدال پر قائم رکھنے کے لیے کوششیں بروے کار لائیں۔ یہ مقصود نہیں کہ ہر مسئلہ کے متعلقہ اختلافات کھول کھول کر عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کردیں اور ان کے لیے خلفشار کا باعث بنیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ اختلافات علما کی نظروں کے سامنے رہیں۔ وہ فقہی اور اجتہادی نوعیت کے مسائل کوان کے اصل تناظر میں دیکھیں اور بوقت ضرورت اس کا اظہار کرنے میں بھی جھجک محسوس نہ کریں۔
کیا معاصر جہاد ’منہاج دین‘ کے خلاف ہے؟
محمد زاہد صدیق مغل
ماہنامہ الشریعہ، شمارہ اکتوبر ۲۰۱۱ میں فاضل مصنف جناب اویس پاشا قرنی صاحب کا مضمون ’عصر حاضر میں غلبہ اسلام کے لیے جہاد‘ نظر سے گزرا۔ صاحب مضمون نے اپنے مضمون میں دو مقدمات پر بحث کی ہے۔ اولاً، موجودہ دور میں نصوص دعوت کو منسوخ ٹھہرانے والے حضرات کا رد (مضمون کے اس حصے سے ہمیں اتفاق ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا انکار کرنا کسی طور درست نہیں)۔ ثانیاً، موجودہ دور میں جہادی جدوجہد کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ منہاج شریعت کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اس ضمن میں فاضل مصنف بنیادی طور پر دو دلائل پیش کرتے ہیں: (۱) جہادی جدوجہد ناکامی و نقصان سے عبارت ہے، لہٰذا اسے ترک کردینا چاہیے (گو کہ اس نکتے پر وہ تفصیلی دلیل قائم نہیں کرتے، البتہ اسے ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر فرض کرکے اپنے دلائل کی عمارت قائم کرتے چلے جاتے ہیں)۔ (۲) موجودہ صورت حال میں جہادی حکمت عملی سنت نبوی کے منہاج کے خلاف ہے۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کا حکم مدینہ میں مشروع ہوا نہ کہ مکہ میں، جبکہ موجودہ حالات میں مسلمان مکی دور سے گزر رہے ہیں اور مکی دور کا تقاضا صرف اور صرف دعوت، تبلیغ و تنظیم سازی وغیرہ پر ساری توجہ مرکوز کردینا ہے۔
ہمیں نہیں معلوم پاشا صاحب کا فکری تناظر و پس منظر کیا ہے (کسی دلیل کا تجزیہ کرنے کے لیے صاحب دلیل کے فکری حدود اربعہ معلوم ہونے سے بہت مدد مل جاتی ہے)، البتہ ان کے انداز استدلال سے یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ ان کا فکری تعلق شاید تنظیم اسلامی سے ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)۔ چونکہ ہمیں اس بابت کوئی حتمی علم نہیں، لہٰذا ہم یہاں تنظیم اسلامی کے طرز فکر کو بنیاد بنا کر کوئی تنقید نہیں کریں گے۔ جہاں تک ان کی پہلی دلیل کا تعلق ہے، اس کا تفصیلی جائزہ ہم نے اپنے مضمون ’’معاصر منکرین خروج کے استدلال کا جائزہ‘ ‘ میں پیش کیا ہے (جو ان شاء اللہ عنقریب منظر عام پر آئے گا)۔ یہاں بس اتنا اصولی جواب کافی ہے کہ :
- فائدوں اور نقصانات کا تعلق حکمت عملی کے باب سے ہے نہ کہ اصل دلائل شرعیہ سے، لہٰذا ان کی بنا پر کسی شے کی مخالفت ایک اجتہادی رائے سے زیادہ کچھ نہیں۔
- ’فائدے اور نقصان‘ کا تعین طرز فکر سے ہوتا ہے، یعنی ایک شے جو کسی ایک نقطہ نظر کے لحاظ سے فائدہ سمجھی جاتی ہے، عین ممکن ہے کسی دوسرے نقطہ نظر کے اعتبار سے نقصان قرار پائے۔ جس طرح منکرین معاصر جہاد کو اپنے نقطہ نظر سے فائدے اور نقصان کا تعین کرنے کا حق حاصل ہے، بالکل اسی طرح دوسروں کو بھی اس کا حق حاصل ہے۔
- نتائج کی بنیاد پر کسی شے کا حکم متعین کرنا اصول فقہ میں ’سد الذرائع‘ کہلاتا ہے اور یہ اصول فقہ کا ایک پیچیدہ باب ہے جہاں فیصلہ کرتے وقت کسی ایک نہیں، بلکہ تمام عوامل اور پہلووں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا حکم لگاتے وقت کسی ایک پہلو پر ہی ساری توجہ مرکوز نہیں کی جاسکتی۔
- یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ہر جدوجہد محتاط اندازے و تخمینے کے مطابق ہی کی جاتی ہے جس میں کامیابی و ناکامی کے امکانات ’جدوجہد کرنے والوں‘ کے خیال میں برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان امکانات کا تخمینہ لگانا ’جدوجہد سے باہر‘ کسی بیرونی ادارے، افراد یا تحریک کا نہیں بلکہ خود جدوجہد کرنے والوں کا کام ہوتا ہے اور اس ضمن میں انہی کا قول ’قول فیصل‘ سمجھا جانا چاہیے کیونکہ جہاد کرنے والا گروہ زیادہ بہتر طور پر جان سکتا ہے کہ اس کے پاس کتنی قوت ہے اور کب اس کو استعمال کیا جائے گا۔ پھر کامیابی و ناکامی کے امکانات طے کرنے کاکوئی سائنٹفک معیار و طریقہ کار موجودہ نہیں ہوتا اور نہ ہی جدوجہد سے پہلے اس کی عوامی مقبولیت کا کوئی معین اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی قریب میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جب آغاز جدوجہد میں ناقدین اسے ناکامی کا سرٹیفیکیٹ دے چکے تھے، لیکن حالات و واقعات نے ایسی کروٹیں لیں کہ طاقتور ترین دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگیا۔
- پھر امت کو جہادی جدوجہد ترک کرکے جن طرق کی طرف دعوت دی جارہی ہے، بذات خود ان طریقوں کو بھی نتیجیت پسندی کے اصول پر پرکھ کر دیکھ لیا جانا چاہیے کہ ان کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی تعمیر کے کام میں کس قدر ’خیر‘ جمع کیا جا سکا ہے؟ کیا نصف صدی سے لمبے عرصے پر محیط غیر جہادی جدوجہد نے آج سیاسی اسلامی تحریکات کو ایسی بند گلی میں لا کھڑا نہیں کیا جس سے آگے انہیں کوئی راہ نہیں سوجھتی ؟
- منکرین معاصر جہاد کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ موجودہ دور کے اصل چیلنج یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے جواب میں امت مسلمہ میں برپا جدوجہد کی ہمہ گیریت کا درست ادراک نہیں رکھتے، لہٰذا وہ معاصر جہادی جدوجہد کو اصلاحی جدوجہد کا متبادل و مد مقابل سمجھتے ہیں، جبکہ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کا تکملہ ہیں۔ (ان نکات کی مزید تفصیل کے لیے راقم کا مضمون ملاحظہ فرمائیے گا)۔
اب ان کی دوسری دلیل پر تبصرہ پیش کیا جاتا ہے۔
پاشا صاحب کی پیش کردہ یہ دلیل کوئی نئی نہیں، بلکہ ایک عرصے سے معاصر جہاد کے خلاف دہرائی جارہی ہے۔ (معاصر جہاد پر اس قبیل کے دیگر اعتراضات کے تجزیے کے لیے دیکھیے حامد کمال الدین صاحب کا مضمون ’معاصر جہاد اور کچھ عمومی اشکالات‘، ایقاظ، جولائی تا دسمبر ۲۰۱۱)۔ چلیے ایک لمحے کے لیے قرآنی آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے بارے میں علمائے مفسرین کی رائے سے صرف نظر کرتے ہوئے پاشا صاحب کی اس ترتیب احکام اور ’حکمت منہاج ‘ کے فلسفے کو مان لیتے ہیں، پھر بھی ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ’مکی و مدنی دور کے منہاج میں فرق کرنے والی شے آخر کیا تھی؟‘ ہماری دانست میں اس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مدینہ میں ایک ریاست میسر آگئی تھی۔ ہم تاکید کے لیے پھر کہے دیتے ہیں کہ منہاج کا فرق کرنے والی شے مدینہ میں باقاعدہ ایک ریاست کا میسر آجانا ہی تھا نا؟ اگر ایسا ہی تھا جیسا کا امر واقعہ ہے اور یہ دلیل دینے والے حضرات کو بھی قبول ہے تو پھر دور حاضر میں مسلمانوں نے جو یہ درجنوں مسلم (یا جیسی تیسی اسلامی) ریاستیں قائم کر رکھی ہیں، کیا اتنی طویل المدت اور ڈھیر ساری ریاستوں کے قیام کے بعد بھی مدنی دور کا آغاز نہیں ہوا؟ سیرت نبوی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ’مدینہ میں ایک چھوٹی سی اور نہایت کمزور اسلامی ریاست قائم ہوتے ہی احکاما ت جہاد اور عملاً جہاد شروع ہوجاتا ہے‘، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کروڑوں کی آبادیوں اور وسائل والے علاقوں پر مسلم حکومتیں قائم ہوجانے کے بعد بھی جہاد منہاج سنت کے خلاف قرار دیا جارہا ہے؟ آخر اس مدنی دور کا آغاز کس طلوع آفتاب سے ہوگا؟ یہ دلیل دینے والے حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے منہاجی فلسفے کی روشنی میں ان ’شرائط‘ (ہم یہ لفظ فقہی اصطلاح میں استعمال کررہے ہیں) کا ٹھیک ٹھیک تعین فرمادیں جو مدینہ میں تو جہادی حکمت عملی کا وجہ جواز بن سکتی تھیں، لیکن موجودہ حالات میں مانع ہیں۔ (اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ پاشا صاحب کا تعلق تنظیم اسلامی سے ہے تو ہم ان کی فکر کو تنظیم کے فکری تناظر کے ساتھ ملا کر دکھاتے کہ اس میں مزید کتنے ابہامات ہیں)۔
عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ’منہاجی فلسفے‘ کو بطور دلیل پیش کرنے والے حضرات کو تو موجودہ حالات میں نہ صرف یہ کہ جہاد کا سب سے بڑا حامی ہونا چاہیے، تھا بلکہ کم از کم پاکستان کو اس کا بیس کیمپ بنانے پر اصرارکرنا چاہیے تھا کہ پاکستانی ریاست تو (بقول ان کے) بنائی ہی اسلام کے لیے گئی تھی۔ چنانچہ جب ریاست بھی بن گئی تو اب مکی دور کی دہائی کا کیا مطلب؟
چونکہ اس منہاجی دلیل کے منطقی مضمرات انتہائی خطرناک ہیں (مثلاً اس دلیل کے اطلاق کی رو سے سود، صوم و حج وغیرہم جیسے بہت سے احکامات پر آج عمل کرنا منہاج دین کے خلاف ٹھہرے گا کیونکہ یہ بھی مدینہ میں مشروع ہوئے)، لہٰذا ان سے بچنے کے لیے اپنی دلیل میں موجود ضعف کو پیوندکاری کے ذریعے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ اپنی دلیل پر وارد ہونے والے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے پاشا صاحب فرماتے ہیں: ’’یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی نظیر یا مثال کا سوفیصد انطباق نہیں ہوتا بلکہ کسی نسبت سے اُس کا اطلاق ہوتا ہے اور کسی پہلو سے نہیں بھی ہوتا۔ اُسوۂ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ عقل عام کی بات ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں‘‘۔ بالکل جناب، یہ بات درست ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں تعلق کسی مخصوص نسبت ہی سے قائم کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں آخر ’آج‘ یہ فیصلہ ’ کون‘ اور ’کس پیمانے‘ کی بنیاد پر کرے گا کہ اس دلیل میں مقیس اور مقیس علیہ کی مماثلت و عدم مماثلت کن دینی معاملات میں معتبر اور کن میں غیر معتبر مانی جائے گی؟ پھر اگر کوئی شخص یا جماعت اپنے تئیں یہ فیصلہ کرلے تو سوال یہ ہے کہ امت کے حق میں اس فیصلے کی ’شرعی حیثیت‘ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے اس کی دینی حیثیت ذاتی اجتہاد سے بڑھ کر کوئی اور تو ہو نہیں سکتی۔ تو پھر جس طرح ایک شخص یا جماعت کو اپنا ’حق اجتہاد ‘ استعمال کرکے امت یا اپنی جماعت سے حکم جہاد کو معطل کرنے کی اجازت مل جائے گی، کیا اسی طرح دوسرے گروہوں کو بھی اجتہاد کے ذریعے اپنے فلسفے و مطالعے کی بنیاد پر چند دیگر احکامات معطل کرلینے کا حق حاصل نہیں ہو جائے گا؟
مثلاً کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں جہاں استخلاف فی الارض کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے، وہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب بھی انھیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو وہ چار کام کریں گے: اقامت صلوٰ ۃ ،زکوٰۃ کا قیام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر (الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلوۃ واتو الزکوۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر)۔ اسلامی ریاست کے یہ چار بنیادی وظائف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اس آیت سے منکرین جہاد کی طرح کوئی منکر صلوٰۃ و زکوٰۃ یہ استدلال کرسکتا ہے کہ جناب زکوٰۃ وصلوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلامی ریاست کا فریضہ اور وظیفہ ہیں، لہٰذا مسلمانوں پر یہ تمام کام بھی اسلامی ریاست کے قیام تک ترک کرنا لازم ہے۔ کیونکہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں اور اسلامی ریاست موجود نہیں، لہٰذا مساجد تعمیر نہ کی جائیں نیزنظام صلوٰۃ کا اہتمام بند کیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ وصول کرنے والی ریاست نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ بھی ساقط ہے اور ساتھ ہی ’منہاجی فلسفے‘ اور ’حکمت دین‘ کی بنیاد پر یہ استدلال بھی پیش کردے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مکہ میں مسجد کا کوئی اجتماعی بندوبست کیا اور نہ ہی کسی سے زکوٰۃ لی۔ اسی طرح اچھے کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ بھی اسلامی ریاست کی سرپرستی اور موجودگی میں ہی اداکیا جاسکتا ہے، لہٰذا ان کاموں کو بھی ترک کردیا جائے۔ کیوں جی، کیسا رہا یہ اجتہاد اور منہاج دین کا فلسفہ؟
اگر کسی کا جواب یہ ہے کہ ’موجودہ حالات کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا مقصود ہے‘ تو سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کی رعایت کرتے ہوئے آخر جہاد کرنا ہی کیوں مقصود نہیں؟ کیا کوئی صاحب علم یہ ثابت کرسکتا ہے کہ آج حالات ایسے ہوگئے ہیں کہ جہاد ’عملاً ناممکن ‘ ہوچکا ہے؟ اگر یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ امر واقعہ ہے، تو اگر حالات کی رعایت کرتے ہوئے غلبہ دین کے دیگر طرق کے ذریعے جدوجہد کرنا جائز ہے تو جہاد ہی کیوں شجر ممنوعہ ہے؟ اگر مسئلہ ’موجودہ حالات کی رعایت کے ساتھ عمل کرنے‘ کا ہی ہے تو اس معاملے میں منکرین کا ’تجزیہ حالات‘ ہی کیوں حجت مانا جائے؟ کیا کسی دوسرے فرد یا گروہ کو حالات کے اپنے تجزیے کی بنیاد پر جہاد کرنے کا حق حاصل نہیں ہو سکتا؟ پس جس طرح حالات کی رعایت کرتے ہوئے پاشا صاحب جیسے حضرات دیگر احکامات پر عمل ممکن سمجھتے ہیں، جہادی جدوجہد کرنے والے گروہ جہاد کو بھی ممکن سمجھتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے منہاجی فلسفے عام کرنے کا مطلب دین میں رخنہ اندازی کرنے کے راستے کھولنا ہے ، یہی وجہ ہے کہ روایت پسند علمائے کرام نے الیوم اکملت لکم دینکم کی روشنی میں فرمایاہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی شخص یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی فلسفے یا اجتہاد کی روشنی میں کسی دینی حکم کو عبوری طور پر ہی سہی منسوخ قرار دے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاشا صاحب جس ذہنیت (دین کے بعض احکامات کو مخصوص حالات میں منسوخ ٹھہرانے) کو اپنے مضمون میں رد کرنے نکلے تھے ، شعوری یا غیر شعوری طور پر بذات خود اسی ذہنیت کا شکار نظر آتے ہیں۔
مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوائے نبوت اور مولانا وحید الدین خان کا تجاہل عارفانہ
مولانا مفتی محمد سعید خان
جناب مولانا وحید الدین خان صاحب ، عصر حاضر کی ان نابغۂ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے قارئین کا پوری دنیا میں ایک حلقہ موجود ہے۔لوگوں کوان کی تحریرات کاانتظار رہتا ہے اور ہزاروں افراد نہ صرف یہ کہ ان کے مشن سے وابستہ ہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں انہیں جو ہدایات مولانا کی طرف سے ملتی ہیں، وہ دل وجان سے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے چند ایک پڑھے لکھے حضرات میں ان کانام شمار کیاجاتا ہے اوران کی جو پذیرائی مغربی ممالک میں ہورہی ہے، اس کااندازہ کچھ انہی حضرات کو ہوسکتا ہے جو ان کے شمارے ’’الرسالہ‘‘ کے مستقل قاری ہیں۔ ان کی شخصیت، جیسا کہ روز اول سے ہوتا چلا آیا ہے، موضوع سخن رہی ہے ،اب بھی ہے اور جب وہ دنیا میں نہیں ہوں گے، اس وقت بھی اپنے نقاد اور مداحوں کے درمیان گھری رہے گی۔ الرسالہ میں ان کی بعض تحریرات شہ پارہ ہیں اور ہماری نئی نسل کی رہنمائی میں ہمیشہ معاون ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس تصویر کادوسرا رُخ یہ ہے کہ ان کی بعض تحریرات اہل ایمان ودانش کے لیے سخت خلجان کا موجب بھی بن جاتی ہیں۔ انگلی کو دانتوں میں دبائے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ جس شخص اورا س کے قلم کی صلاحیتیں اسلام کے مخالفین اور شکوک وشبہات کی جڑ کھودنے میں صرف ہو رہی ہیں، انہی صلاحیتوں کا رُخ پھرا اور کوئی ایسی تحریر وجود میں آگئی جو اہل کفر اور افواج باطل کے لیے ایک عمدہ ہتھیارکا کام دے سکے۔دودھاری تلوارجب کھنچ جائے اور دشمنوں ہی کونہیں دوستوں کو بھی اپنا دفاع کرنا پڑے تو اس کاٹ کی مدح سرائی کیونکر ہو۔
ماہ اکتوبر 2011ء کا شمارہ ’’الرسالہ‘‘ نظرنواز ہوا اور اس ماہ کا موضوع ہے ’’ختم نبوت‘‘۔ ختم نبوت جو ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ اور کفر واسلام کا ایک امتیازی نشان ہے ، مسلمانوں میں کبھی بھی متنازعہ نہیں رہا۔ جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا،اسے اور اس کے ماننے والوں کو اُمت مسلمہ نے کبھی بھی اپنی صفوں میں کوئی جگہ نہیں دی۔دعوائے نبوت اس قدر ہولناک ہے کہ اس کے مدعی کے کلام کی توجیہ وتاویل کبھی بھی قابل اعتبار و التفات نہیں ٹھہری ۔اب تک جس آخری شخص نے نہایت شدّو مد سے دعویٰ نبوت بھی کیا اور انہیں اپنے ماننے والوں کی جماعت بھی میسر آئی، وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تھے۔ الرسالہ کے اس ’’ختم نبوت‘‘ نمبر میں ، اس دعوائے نبوت کی تاویل کرتے ہوئے جناب مولاناوحید الدین خان صاحب اس دعوے کی نہ صرف یہ کہ نفی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جناب مرزا غلام احمد صاحب کے دعوائے نبوت کی تاویل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:
’’مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ظلِّ نبی ہوں، یعنی میں نبی کا سایہ ہوں ۔اس طرح کے قول کو ایک طرح کی دیوانگی تو کہا جاسکتا ہے، لیکن اس کو دعوائے نبوت نہیں کہا جا سکتا۔‘‘ (ماہنامہ الرسالہ، اکتوبر 2011ء ، ص:13)
معروضہ یہ ہے کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہمیشہ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور بالکل صاف اور واضح الفاظ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول کہتے رہے ہیں۔ان کی زبان اور قلم ہمیشہ اپنے سننے اور پڑھنے والوں سے یہی تقاضا کرتی رہی ہے اور اب بھی ان کی جماعت کا اصولی مؤقف یہ ہے کہ ان کے مقتدا اورپیشوا جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی اور رسول مانا جائے۔ خود جناب مرز اغلام احمد صاحب قادیانی تحریر فرماتے ہیں :
’’حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفا ظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ ۔‘‘
پھر آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں :
’’چنانچہ وہ مکالماتِ الہٰیہ جو براہین احمد یہ میں شائع ہوچکے ہیں ، ان میں سے ایک وحی اللہ (اللہ تعالیٰ کی وحی)ہے: ھو الذی ارسل رسولہ بالھدیٰ ودین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ۔ (دیکھو براہین احمد یہ ، ص:۴۹۸)اس میں صاف طور پراس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے ۔‘‘
چند سطروں کے بعد تو انہوں نے ایسی عبارت لکھی ہے، جو کسی بھی اشتباہ یا تاویل کا موقع فراہم نہیں کرتی:
’’یہ وحی اللہ (اللہ تعالیٰ کی وحی)ہے: محمد رسول اللّٰہ والذین معہ اشدآء علی الکفار رحماء بینھم، اس وحی الٰہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی ۔‘‘
(ان تمام عبارات کے لیے ملاحظہ ہو روحانی خزائن ، جلد :18 ص:206-207۔ ایک غلطی کا ازالہ، ص:2-3)
صرف اس ایک کتاب ’’ایک غلطی کا ازالہ ‘‘ ہی نہیں بلکہ ان کی متعدد کتابوں میں بار بار اس دعوے کی تکرار کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں ۔ وہ اپنی وحی کو بھی قرآن کریم کے ہم پلّہ قرار دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :
’’مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر۔‘‘ (روحانی خزائن ، جلد:17، ص:454۔(ب)اربعین لاتمام الحجۃ علی المخالفین نمبر4، ص:112)
جناب مولانا وحید الدین خان صاحب سے درخواست ہے کہ اگر اب تک انہوں نے احمدی حضرات کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیاتو اُن کی کتاب ’’روحانی خزائن ‘‘کو غور سے پڑھیں اور کسی بھی شخص یافریق کی بات سنے،ان کا لٹریچر پڑھے اور ان کے متعلق کسی بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر کوئی حکم لگانا ، بعیداز انصاف ہے ۔ان کی جماعت کے کسی بھی ذمہ دار فرد سے اگران کا مسلک دریافت کیا جائے تو وہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نبوت ورسالت کا ہی اقرار کرتے نظرآئیں گے ۔
یہ تمام تحریر بھی اس صورت کے لیے ہے کہ یہ فرض کر لیاگیا کہ جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کی نظر سے جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ایسی تحریرات اور کتابیں نہیں گذریں، لیکن اگر وہ ان کی کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تو پھر وہی مثل صادق آتی ہے کہ ہم سوئے ہوئے کو تو بیدار کرسکتے ہیں ، اس کو نہیں جو سویا بن رہا ہے ۔
مرزا صاحب نے اپنی تحریروں میں بروزی نبوت کا تصور پیش کیا ہے۔ عربی زبان میں بَرَزَ کا لفظ ظہور اور کسی چیز یا کام یا صلاحیت کے ظاہر ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے میں بھی یہ ’’بروز ‘‘شامل ہے۔ان کے مذہب میں یہ بات ہے کہ ان کے دیوتا آسمان سے اُترے اور مختلف انسانوں کے روپ دھار کر انہوں نے بروز کیا یعنی ظہور یا ظاہر ہوئے۔ وہ ظاہر میں انسان لیکن در حقیقت خدا تھے۔جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی ہندوؤں کے اس نظریے کو ایک اور رنگ میں پیش کیا اور وہ یہ کہ ہندو تو خداؤں کے بروز کے قائل تھے، انہوں نے نبوت کو بروزی بنادیا کہ ان کے اندر تو حضرت رسالت مآب سمائے ہوئے تھے اور ظاہر میں جسم ان کا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی ایک کتاب’’ایک غلطی کا ازالہ ‘‘میں واضح طور پر تحریر فرماتے ہیں :
’’بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔‘‘
یعنی آقائے نامدار حضرت رسالت مآب e میرے اندر سماگئے ہیں ۔ میں ظاہر میں تو مرزا غلام احمد ہوں` لیکن اندر سے محمد رسول اللہ ہوں۔اعاذنا اللہ۔پھر اپنی اسی کتاب میں چند سطروں کے بعد مزید تحریر فرماتے ہیں:
’’میں بروزی طور پر آنحضرت ہوں۔‘‘ (روحانی خزائن،ج:18، ص:212 (ب)ایک غلطی کا ازالہ ۔ص:8)
جناب مولانا وحید الدین خان صاحب اور ان کی تحریرات سے متاثر ہونے والے حضرات وخواتین کو اس نقطے اور عبارات پر غور فرماناچاہیے کہ جناب مرزا صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ تو یہ بتارہے ہیں کہ میں اندر سے تو حضرت خاتم الابنیاء ہوں اور ظاہر میں مرزا غلام احمد ہوں۔ ایسے عقائد تو ان قوموں کے ہوا کرتے تھے جو اپنے دیوتاؤں کو خدا مانتے تھے اور ہیں۔ اسلام نے بھی کبھی کوئی ایسی تعلیم دی ہے؟کل کو یا زمانۂ ماضی میں اگر کوئی جاہل اور گمراہ صوفی یہ دعویٰ کرے کہ وہ بروزی طور پر خدا ہے تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا ؟وہ دنیا کو اس عقیدے کی دعوت دے کہ میں بروزی اللہ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے اندر سما گیا ہے اور میں فقط ظاہر میں انسان ہوں، حقیقت میں تمہارا پروردگار ہوں ۔ کیا یہ دعویٰ مسموع ہوگا؟ اس لیے جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کن کا دفاع فرمارہے ہیں، چاہیے کہ غور فرمالیں اور جو لوگ دین میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کہیں ان کی راہ کھوٹی نہ ہوجائے۔
جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ظِلّی نبی ہیں جناب مولانا وحید الدین خان صاحب تحریر فرمارہے ہیں کہ:
’’انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ظِلِّ نبی ہوں یعنی میں نبی کا سایہ ہوں۔‘‘ (الرسالہ،بابت ماہ اکتوبر 2011ء، ص:13)
بات یوں نہیں ہے جناب مرزا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ حضرت رسالت مآب علیہ الصلاۃوالتسلیم کا سایہ (ظل)ہیں بلکہ انہوں نے تو یہ دعویٰ فرمایا کہ میں نبی ہوں اور میری نبوت کو حضرت صاحب الرسالۃ محمد رسول اللہ سے وہی نسبت ہے جوکہ سایے کو اصل سے ہوتی ہے۔ جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریر کے مطابق تو ان کا اصل دعویٰ محض اصل اور سایے(ظِلّ) کے زمرے میں آتا ہے، لیکن در حقیقت ان کا دعویٰ اپنی چھوٹی نبوت اور حضرت رسالت مآب کی بڑی نبوت کا ہے کہ میں جو کم درجے کی چھوٹی نبوت رکھتا ہوں، اس کے مقابلے میں ایک بڑی نبوت بھی ہے، وہ حضرت رسالت مآب کی ہے۔ وہ تو بہت صاف ،واضح اور بغیر کسی جھجک کے یہ دعویٰ فرماتے ہیں:
’’میں ظلّی طور پر محمد ہوں۔‘‘ (روحانی خزائن ج:18 ،ص:212 (ب)ایک غلطی کا ازالہ،ص:8 )
اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دعویٰ کردیا ،ایسادعویٰ کہ جو ان کے اس دعوے کو نہیں مانتے اور اس کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ افرادجو جناب مرزا صاحب کو ان کے دعوے میں سچا مانتے ہیں، دونوں کے درمیان مسلم اور غیر مسلم کی لکیر کھچ گئی۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا:
’’سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔‘‘ (روحانی خزائن ج:18، ص:231۔ دافع البلاء و معیار اھل الاصطفاء: ص:15)
ایک اورحوالہ ملاحظہ ہو :
’’غرض اس حصہ کثیر وحی الٰہی اور امور غیبیہ میں اس اُمت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس اُمت میں سے گذر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا ۔پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔‘‘ (روحانی خزائن، ج:22،ص:406-407۔ حقیقۃ الوحی ، ص:391)
جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ انہوں نے اپنے پرچے ’’الرسالہ ‘‘ میں جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی وکالت ، اور ان کے جرم کو جو کم کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا یہ دعاوی اور عبارات ان کی نظر سے نہیں گزریں؟ اگر نہیں تو یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے کہ وہ جس کی وکالت فرماتے ہیں، وہی ان کے دعوے کی تردید کرتا چلا جاتا ہے۔ ان کی عبارتیں ایک سے ایک بڑھ کر دعوائے نبوت ورسالت کی ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہی نہیں۔ بغیر مطالعہ کیے عقیدۂ ختم نبوت جیسے حساس اور بنیادی عقیدے پر اس طرح کا تبصرہ کیسے مناسب ہے؟ اور اگر ان کی نظر سے یہ تمام کتابیں اور جناب مرزا صاحب کے دعوے گزر چکے ہیں تو پھر کیا اسے تجاہل عارفانہ سمجھا جائے! جناب مولانا وحید الدین خان صاحب چاہیے کہ اپنے الفاظ ، تحریر اور عقیدے سے رجوع فرمائیں۔ اس مسئلے کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے اور اس نزاکت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی اس تحریر کی بنیاد پر کوئی نیا فرقہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اُمت کی حفاظت فرمائے، پہلے ہی بہت ٹکڑے اور فرقے بن چکے ہیں، اب کہیں کوئی نیا فرقہ یا فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔
مکاتیب
ادارہ
(۱)
برادرم مولانا زاہد اقبال صاحب
السلام علیکم، مزاج گرامی؟
آپ کی کتاب ’’اسلامی نظام خلافت‘‘ میں نے دیکھ لی ہے اور اس پر تقریظ بھی لکھ دی ہے، مگر میں اس سلسلہ میں بعض تحفظات رکھتاہوں جو الگ درج کر رہا ہوں۔ انہیں غور سے دیکھ لیں اور اگر میری گزارشات آپ کے ذہن میں آجائیں تو متعلقہ مقامات کا از سر نوجائزہ لے لیں۔
۱۔کتاب قرآن وسنت اور فقہ اسلامی کے علمی ذخیرے کی بنیاد پر لکھی گئی ہے اورآج کے عالمی حالات اور معروضی حقائق کی طرف توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ اگر خلافت کا نظام آج سے دوسوسال قبل کے ماحول میں قائم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب کافی ہے، لیکن اگر آج کی دنیا میں خلافت کے نظام کی بحالی مقصود ہے تو یہ مواد اور تجزیے قطعی طور پر ناکافی ہیں اوریہ موجودہ مسائل کا حل پیش نہیں کرتے۔
۲۔خلافت کے لیے سنت کے حوالے سے معیار قائم کرنے میں جو حوالہ پیش کیاگیاہے، وہ بہت بہتر ہے، لیکن اس کے لیے مسلم شریف کی یہ روایت بھی شامل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی کہ ’’تمہارے اچھے حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں‘‘۔ میرے نزدیک اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہونا اور باقی رہنا ضروری ہے اور اس کے لیے عملی طور پر حالات کے تحت کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔
۳۔ انعقاد خلافت کا ایک صورت میں صرف ’’ارباب حل وعقد‘‘کو ذریعہ قرار دیاگیاہے جو درست نہیں ہے۔ امامت وخلافت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کا بنیادی اختلاف ہی یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ منصوص ہے جو نامزدگی اور خاندان کی بنیاد پر طے ہوتاہے جبکہ ہمارے نزدیک خلافت نہ منصوص ہے اور نہ ہی خاندانی ہے، بلکہ اسے امت کی صوابدید اور اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے اور امت سے مراد امت ہے، صرف ’’اہل العقد والحل ‘‘نہیں ہیں۔ آپ نے خود حضرت عمرؓ کے ارشاد میں ’’عن غیر مشورۃ من المسلمین‘‘ کا جملہ نقل کیاہے، اس لیے خلیفہ کا انتخاب پوری امت کا حق ہے۔ حضرت عمرؓ کے اس خطبہ کو بخاری شریف میں دیکھیں تو اس میں یہ جملہ بھی ملے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے حقوق اور اختیارات کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔
۴۔ خلافت کے نظام میں صرف شوریٰ نہیں، بلکہ نمائندگی بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے قیدیوں کی واپسی کے لیے بارہ ہزار پر مشتمل اسلامی لشکر کی اجتماعی رائے کو کافی نہیں سمجھا تھا، بلکہ ’’نقبا‘‘ کے ذریعہ ان کی رائے الگ الگ طور پر معلوم کی تھی، اس لیے جہاں علمی مسائل کی بات ہوگی، وہاں شورائیت کے نظام میں وہ تمام افراد حصہ دار ہوں گے جن کے حقوق حکومتی فیصلوں اور اقدامات سے منسلک ہوں گے۔ بخاری شریف میں اس حوالہ سے تفصیلی روایت موجود ہے، اسے توجہ سے دیکھ لیں۔
۵۔خلافت کے لیے تسلط کو ’’نظریہ ضرورت‘‘ کے تحت ذریعہ تسلیم کیا گیاہے کہ اگر کسی وقت ایساہوجائے تو فتنہ وفساد سے بچنے کے لیے اسے قبول کر لیا جائے گا، لیکن اسے ایک مستقل طریق انتخاب اور انعقاد خلافت کے ایک باقاعدہ ذریعہ کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے۔ بالخصوص آج کے دور میں ایک مستقل ’’طریقہ انعقاد وخلافت‘‘ کے طور پر پیش کریں گے تو اس سے کسی متفقہ خلیفہ کا انتخاب تو ممکن نہیں رہے گا، البتہ عالم اسلام میں اس حوالے سے سو ڈیڑھ سو مقامات پر خانہ جنگی ضرور ہو جائے گی۔
۶۔میرے نزدیک آج کے دور میں خلافت کے انعقاد کی صرف ایک ہی صورت عملاً ممکن ہے کہ عالم اسلام میں آٹھ دس مقامات پر اسلامی امارتیں قائم ہوں جن کی بنیاد شوریٰ اور نمائندگی پر ہو۔ وہ انہی دو بنیادوں پرآپس میں کنفیڈریشن قائم کرکے اپنے اوپر خلافت کا ادارہ قائم کرلیں اور ا س کے حق میں ضروری اختیارات سے دست بردار ی اختیار کر کے باہمی مشورہ سے امیرا لمومنین کا انتخاب کرلیں۔ اس کے سوا آج کے دور میں اسلامی خلافت کے قیام کی کوئی صورت عملاً ممکن نہیں ہے ۔
۷۔خلافت کے لیے قریشیت کی شرط کو میں بھی ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اس کے لیے آپ نے اولوالامر کے غیر قریشی ہونے سے جو استدلال کیاہے، وہ بے محل ہے، اس لیے کہ قریشی ہونے کی شر ط کی بحث صرف خلیفہ کے لیے ہے۔ اس کے ماتحت اولو الامرکے لیے قریشی ہونے کو کسی نے بھی شرط قرار نہیں دیا۔
۸۔آپ نے ایک طرف ’’غلام‘‘کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے رائے دینے کے حق سے محروم کردیاہے اوردوسری طرف استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ کی روایت بھی نقل کردی ہے۔ اس تعارض کا آپ کے پاس کیا حل ہے ؟اگر اسے شرعاً یہ دونوں حق حاصل ہیں تو اسے اس نظام میں کسی نہ کسی درجہ میں شریک کرنے کے لیے آپ کو راستے نکالنا پڑیں گے۔
۹۔ اقوا م متحدہ عالم اسلام پر( غلط یا صحیح )جو حکمرانی کررہی ہے، وہ یکطرفہ اور جبری نہیں ہے بلکہ ایک معاہدہ کے تحت ہے جس میں ہم باضابطہ طورپر شریک ہیں اور اس سے نکلنے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں، اس لیے اس کی ساری ذمہ داری اقوام متحدہ پر ڈال دینا مناسب نہیں ہے۔
۱۰۔ نیز بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی ہمیں کوئی اصول قائم کرناہوگا۔ جو بین الاقوامی معاہدہ ہمارے اقتدار اعلیٰ اور قرآن وسنت کے منصوص احکا م کے منافی ہے، اسے ہمیں کلیتاً مسترد کردینا چاہیے بلکہ اس میں شامل ہونا بھی غلط ہے، لیکن جو معاملات ہماری خود مختاری کی نفی نہیں کرتے اور قرآن وسنت کے کسی صریح اور منصوص حکم کے منافی بھی نہیں ہیں، انہیں یکسر مسترد کردینا درست نہیں ہوگا۔ تلک عشرۃ کاملۃ
ابو عمار زاہد الراشدی
۲۰۰۶/۱۱/۱
(۲)
مولانا عمار خان ناصر حفظہ اللہ تعالیٰ
السلام و علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
مزاج بخیر
آپ نے اپنے لبنان کے سفر نامے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ رافضی کے پیچھے نماز جائز ہے۔ برائے کرم اس کا حوالہ اگر میسر ہو جائے تو بندہ آپ کا ممنون و مشکور ہوگا۔
(حافظ)محمد فرقان انصاری۔ ٹنڈو آدم
(۳)
مکرمی محمد فرقان انصاری صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔
متعلقہ حوالہ حسب ذیل ہے:
واما الصلاۃ خلف المبتدع فہذہ المسالۃ فیہا نزاع وتفصیل فاذا لم تجد اماما غیرہ کالجمعۃ التی لا تقام الا بمکان واحد وکالعیدین وکصلوات الحج خلف امام الموسم فہذہ تفعل خلف کل بر وفاجر باتفاق اہل السنۃ والجماعۃ وانما تدع مثل ہذہ الصلوات خلف الائمۃ اہل البدع کالرافضۃ ونحوہم ممن لا یری الجمعۃ والجماعۃ، اذا لم یکن فی القریۃ الا مسجد واحد فصلاتہ فی الجماعۃ خلف الفاجر خیر من صلاتہ فی بیتہ منفردا لئلا یفضی الی ترک الجماعۃ مطلقا واما اذا امکنہ ان یصلی خلف غیر المبتدع فہو احسن وافضل بلا ریب لکن ان صلی خلفہ ففی صلاتہ نزاع بین العلماء ومذہب الشافعی وابی حنیفۃ تصح صلاتہ واما مالک واحمد ففی مذہبہما نزاع وتفصیل وہذا انما ہو فی البدعۃ التی یعلم انہا تخالف الکتاب والسنۃ مثل بدع الرافضۃ والجہمیۃ ونحوہم (مجموع الفتاوی، ۲۳/۳۵۵، ۳۵۶)
’’بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنے کے مسئلے میں کچھ اختلاف اور تفصیل ہے۔ اگر تو بدعتی کے علاوہ کوئی دوسرا امام میسر ہی نہ ہو، مثلاًجمعے کی نماز جو صرف ایک ہی جگہ ادا کی جاتی ہو یا عیدین کی نماز یا ایام حج میں حج کے امام کے پیچھے ادا کی جانے والی نمازیں (جبکہ ان سب صورتوں میں امام بدعتی ہو)، تو مذکورہ تمام نمازیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق ہر نیک اور بد کے پیچھے ادا کی جائیں گی۔ امام کے پیچھے ایسی نمازوں کو ترک کرنے کی روش دراصل روافض اور ان جیسے اہل بدعت کی ہے جو (اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے امام کے پیچھے) جمعہ اور جماعت کو درست نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اگر بستی میں ایک ہی مسجد ہو (اور اس کا امام بدعتی ہو) تو گناہ گار امام کے پیچھے نماز ادا کر لینا گھر میں تنہا نماز ادا کرنے سے بہتر ہے تاکہ بالکلیہ نماز باجماعت کا ترک کرنا لازم نہ آئے۔ البتہ اگر آدمی کے لیے بدعتی کے علاوہ دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن ہو تو بلاشبہ یہ طریقہ بہتر اور افضل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کے متعلق علما کے مابین اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہوگی، جبکہ امام مالک اور امام احمد کے مذہب میں اختلاف اور کچھ مزید تفصیل ہے۔ یہ مسئلہ ایسی بدعت (اور اس کے حامل بدعتی امام) سے متعلق ہے جس کا کتاب وسنت کے خلاف ہونا واضح طور پر معلوم ہو، جیسا کہ روافض، جہمیہ اور ان جیسے دوسرے گروہ۔‘‘
میں نے یہ حوالہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ’الجامع الکبیر‘ (الاصدار الثانی ۱۴۲۶ھ/۲۰۰۵ء) سے لیا ہے۔ مطبوعہ نسخوں میں، ممکن ہے جلد اور صفحات مختلف ہوں۔
محمد عمار خان ناصر
۱۹؍ نومبر ۲۰۱۱ء
(۴)
محترم مولانا عمار خان ناصر صاحب مدظلہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ
مزاج بخیر
میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپنے مجھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس فتویٰ کا حوالہ مرحمت فرمایا کہ روافض کہ پیچھے نماز کی گنجائش ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ انتہائی مصروف شخصیت کے حامل شخص ہیں، لیکن حکم قرآنی ’فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون‘ کے مطابق میں آپ کی خدمت میں اس فتوے کے بعد میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو گوش گزار کرکے اس معاملے میں شرح صدر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں گے۔
یہ بات عام ہے اور مشہور ہے کہ ابن تیمیہ نے روافض کے کفر کا فتویٰ دیااور سپاہ صحابہ والے ان کا فتویٰ اپنے موقف کی تائید میں پیش بھی کرتے ہیں۔ جب وہ کافر ٹھہرے تو ان کی اقتدا میں نماز کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہمارے اکابرین نے ہر دور میں شیعہ فرقے سے اتحاد کیا اور ان پر کفر کے فتوے بھی دیے۔ کیا اس سے عام تاثر یہ پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دہرا معیار ہے؟ حال ہی میں دیوبند انڈیا والوں نے ایک فتویٰ شیعہ اثنا عشری کے متعلق دیا کہ ان کے عقیدہ امامت سے انکار ختم نبوت لازم آتا ہے، لہٰذا وہ منکر ختم نبوت ہیں اور دوسری طرف ہم تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ دیوبند انڈیا والوں نے ان کے عقیدہ امامت کے بارے میں یہ حوالہ نقل کیا کہ ہمارے اماموں پر وحی آتی ہے، نئی شریعت آتی ہے، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں اور انہوں نے فتوے میں ان تمام عقائدکو اصول کافی میں کتاب الحجۃ میں درج قرار دیا۔ احقر نے کتاب الحجۃ کو پڑھا، لیکن مجھے اس طرح اس میں کچھ نہ ملا اور سرگودھاکے شیعہ عالم محمد حسین نجفی کی کتاب ’’احسن الفوائد فی شرح عقائد‘‘ کو پڑھا۔ اس میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ اماموں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نبی ہیں اور ان پروحی آتی ہے، یہ کفر ہے۔ امام حلالِ خدا کو حلال اور حرامِ خدا کو حرام بتاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس تمام صورت حال میں آپ برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہمارے علما اور مفتی حضرات اس معاملے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ غالی شیعوں کے عقائد کو دوسرے شیعوں پر چسپاں کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ امید ہے رہنمائی فرمائیں گے۔
حافط محمد فرقان انصاری
(۵)
مکرمی حافظ محمد فرقان انصاری صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
روافض کی تکفیر کے ضمن میں معاصر مفتیان کرام کے طرز عمل کے حوالے سے آپ نے جو سوال اٹھایا ہے، وہ برمحل ہے، البتہ اس کی وضاحت انھی حضرات کی ذمہ داری ہے۔ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں۔ اس کی مزید وضاحت گزشتہ دنوں میں نے ایک علمی مجلس میں کی تھی۔ اتفاق سے اس گفتگو کی نقل تحریری صورت میں میرے پاس محفوظ ہے۔ سردست وہی پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے اس سے ابن تیمیہ کے زاویہ نظر کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔
میں نے عرض کیا تھا کہ:
’’کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی کلمہ گو پر کفر کا فتویٰ لگانا کسی ایسی بات پر جو حقیقت میں کفر نہیں ہے، کوئی فرعی اختلاف ہے، کوئی فہم کا اختلاف ہے، ظاہر ہے کہ اس کا قبیح ہونا اور اس کا ممنوع ہونا واضح ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو محتمل ہے تو اس میں فقہا کا وہ مشہور اصول سب اہل علم نے بیان کیا کہ اگر ننانوے میں سے ایک احتمال بھی ایسا ہے جو کفر سے بچاتا ہے تو اسے کفر سے بچانا ہی چاہیے، جب تک کہ وہ اس کی وضاحت نہ کر دے۔
زیادہ نازک بحث جو بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان فرد یا گروہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے یا اس کو نظریے کے طور پر اپنا لیا ہے جو واقعتا علمی اور فقہی لحاظ سے کفر ہے یا مستلزم کفر ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جو چیزیں کفر نہیں ہیں، فہم کا یا تعبیر کا اختلاف ہے، ان کو کفر قرار دینے کی شناعت تو واضح ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں اہل علم نے، فقہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے تو یہ کفر ہے اور مستلزم کفر ہے تو ایسے افراد کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ زیادہ اہم اور نازک بحث ہے۔ میں اس معاملے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہاں بیان کرنا چاہوں گا جو انھوں نے منہاج السنۃ میں اور اپنے فتاویٰ میں اور بعض دوسری کتابوں میں بیان کیا ہے۔ مجھے ان کا نقطہ نظر درست لگتا ہے۔ دلائل کا موقع آئے گا تو اس پر بات ہوگی۔ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔
ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کوئی فرد یا گروہ ایسا ہے جو کلمہ گو بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ہدایت کا ماخذ بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کفریہ بات کا بھی قائل ہے تو یہاں دو چیزیں ہیں جن کے مابین تعارض ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو اس کی نسبت کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، جبکہ دوسر ی طرف یہ چیز ہے کہ وہ عملاً کوئی ایسا عقیدہ یا نظریہ یا عمل اپنائے ہوئے ہے جو رسول اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ اب ان میں سے کس پہلو کا زیادہ لحاظ کیا جائے؟ اس کے کلمہ گو ہونے کا زیادہ لحاظ کیا جائے یا اس کے نظریے یا عمل کے مستلزم کفر ہونے کا زیادہ لحاظ کیا جائے؟ ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ میرے نزدیک دین کا اورشریعت کے مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گروہوں کے معاملے میں پہلی نسبت کا زیادہ لحاظ رکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اصل میں انسانوں کی دو ہی قسمیں بنتی ہیں۔ یا وہ دائرۂ اسلام میں ہوں گے اور یا دائرۂ اسلام سے باہر ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں اور آپ کے دین کو بحیثیت مجموعی قبول کرتے ہیں، لیکن بعض عقائد میں یا بعض اعمال میں اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو ان کو دائرہ کفر میں شمار کرنے کے بجائے دائرۂ اسلام میں ہی شمار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ گویا ابن تیمیہ کے نزدیک ایسی صورت میں کلمہ گوئی کی جو نسبت ہے، اس کو وزن دینا زیادہ اہم ہے۔
دوسری بات جو انھوں نے اور ان کے علاوہ دوسرے فقہا نے بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی قول یا فعل کے فی نفسہ کفر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے قائل کو یا اس کے فاعل کو بھی ہم کافر کہہ دیں۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ قائل یا فاعل اس وقت کافر ہوگا اگر وہ کسی شبہہے یا کسی تاویل کے بغیر وہ بات کہتا ہو۔ اگر بات تو ایسی ہے جو فی نفسہ کفر ہے، لیکن کہنے والے کو کوئی شبہہ لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کفر نہیں یا کہنے والا اس میں کوئی ایسی تاویل کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہوکہ کفر نہیں ہے تو اس پر اس پر قانونی لحاظ سے کافر کا حکم جاری کرنا صحیح نہیں ہوگا۔
ابن تیمیہ نے اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے صحابہ کے واقعات سے بعض مثالیں دی ہیں۔ مثلاً بعض صحابہ کو کسی شبہے کی وجہ سے قرآن کی بعض آیات کے قرآن کا حصہ ہونے میں تردد تھا۔ (اگرچہ اس میں ایک الگ بحث ہے کہ ایسا تھا یا نہیں، لیکن ابن تیمیہ اس کو مانتے ہیں کہ بعض صحابہ کو شبہہ تھا کہ قرآن کے بعض حصے قرآن کا جزو ہیں یا نہیں۔) اب ظاہر ہے کہ قرآن کے کسی جزو کو قرآن نہ ماننا فی نفسہ ایک بہت نازک اور حساس مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ان حضرات کو اس میں کچھ شبہہ تھا، اس وجہ سے انھیں اس کی رعایت دیتے ہوئے تکفیر نہیں کی گئی۔
اسی طرح فقہا یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کا عملاً کوئی آدمی ارتکاب کرتا ہو تو یہ فسق ہے، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص شریعت کی حرام کردہ چیز کو کسی تاویل کے تحت وہ حلال سمجھتا ہے تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال موجود ہے کہ بعض صحابہ قرآن مجید کی ایک آیت کی غلط تاویل کے تحت شراب کو حلال سمجھتے تھے اور پیتے بھی رہے۔ تو شریعت کی حرام کر دہ ایک چیز جو نص قطعی سے ثابت ہے، اس کو انھوں نے تاویل کے تحت یہ سمجھا کہ اس کی اجازت ہے، اس کی ان کو رعایت دی گئی۔
ابن تیمیہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن گروہوں یا جن افراد کے عقائد یا نظریات میں فی الواقع ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کفر ہیں یا مستلزم کفر ہیں تو ایک تو ان کی کلمہ گوئی کی نسبت کا احترام زیادہ ترجیح کے قابل بات ہے اور دوسرے یہ کہ ان کے ہاں شبہے یا تاویل کا جو پہلو ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ مستند اسلامی عقائد اور نظریات سے ہٹ کر کوئی نقطہ نظر اختیار کرنے والے گروہوں کے بارے میں شریعت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حتی الامکان انھیں دائرۂ اسلام کے اندر رکھا جائے اور علمی تنقید کے ذریعے سے اور باہمی گفتگو کے ذریعے سے ان کے عقائد کی اصلاح کوشش کی جائے۔ ہاں اگر کچھ ایسے زائد وجوہ اور مصالح کسی گروہ کی تکفیر کا تقاضا کریں، مثلاً کوئی گروہ اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کو براہ راست چیلنج کرتا ہو (جیسا کہ مثال کے طور پر قادیانی حضرات اجراے نبوت کے معاملے میں کرتے ہیں) یا ایسا خطرناک ثابت ہو رہا ہو کہ اس کو الگ کر دینا ہی مسلمانوں کی اور اسلام کی اور ملت کی مصلحت کا تقاضا معلوم ہو تو اس صورت میں یہ اقدام بھی کیا جا سکتا ہے۔‘‘
محمد عمار خان ناصر
۲۲؍ نومبر ۲۰۱۱ء
فالج کا ایک نایاب نسخہ
حکیم محمد عمران مغل
مسجد و مدرسہ نیلا گنبد ، انار کلی لاہور کو ہمیشہ ایک مرکزی مقام حاصل رہا ہے۔ یہاں بڑے بڑے علما، فقہا، اساتذہ کرام اور حکما کا جمگھٹا رہا ہے۔ انھی میں ایک ایسے عالم دین تھے جو سرکاری نوکری چھوڑ کر یہاں کے پرسکون ماحول میں آ بسے۔ دین کے علاوہ کوئی کام یا مجلس انھیں پسند نہ تھی۔ عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں کے اسکالر تھے۔ گزر بسر کے لیے مختلف زبانوں کے تراجم کا کا م شروع کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سعودی حکومت اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات، امریکہ، افریقہ تک ان کے نام کا سکہ چلنے لگا۔ بھاٹی گیٹ ہائی اسکول میں عربی کے استاذ تھے، مگر سب کچھ چھوڑ کر مسجد نیلا گنبد میں آ بسے۔ ان کے دو چھوٹے بھائی بھی تھی۔ میرا تعلق ان سے اسکول سے ہی ہوا تھا۔ صبح جتنا کماتے تھے، شام کو خالی ہاتھ گھر جاتے تھے۔ مخلص اتنے کہ کبھی کسی سے انتقام لینے کا نہ سوچتے۔ مجلس بھی بڑی وسیع ہوا کرتی تھی۔ خود اعلیٰ پایے کے ہومیو پیتھ ڈاکٹر تھے، مگر ترجیح ہمیشہ طب اسلامی کو دی۔ فرماتے تھے کہ میں نے ہومیو پیتھک کا کورس کیا ہے، مگر جو بات طب اسلامی یا یونانی میں ہے، وہ دوسرے کسی نظام میں نہیں۔ اسی لیے میں ان کے نزدیک ہوتا گیا۔ میری خواہش تھی کہ ایسے نیک عالم باعمل سے ہر قیمت پر رابطہ استوار ہونا چاہیے۔ یہ تھے حضرت مولانا منظور الوجیدی المعرف مولانا منظور بیگ۔
ایک مرتبہ یوں ہوا کہ تین چار دن تک ملاقا ت نہ ہو سکتی۔ پتہ کیا تو بتایا گیا کہ وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ میں فوراً ہسپتال پہنچا۔ چھوٹا بھائی تیمار داری کر رہا تھا، مگر نہایت پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ تسلی رکھیں، اللہ فضل کرے گا۔ کل میں دوا کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو دیسی دوا نہیں کھانے دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ سے زیادہ مجھے ان معاملات کا پتہ ہے۔ دوسرے دن میں دوا کے ساتھ گیا تو ان کے دونوں بھائیوں کے علاوہ قاری بشارت صاحب مرحوم نے، جن سے میں نے قرآن شریف پڑھنے کا فن سیکھا تھا، فرمایا کہ اس ماحول میں یہ مناسب نہیں۔ میں نے عرض کی کہ ماحول، حالات اور بیماری کی کیفیات کے تحت جو دوا میں لایا ہوں، وہ اللہ کے فضل سے تیر بہدف ثابت ہوگی اور کئی دفعہ تجربہ کی میزان پر یہ دوا پرکھی جا چکی ہے۔ لیکن ان کے چھوٹے بھائی صاحب نے کہا کہ منظور صاحب خود بھی آمادہ نہیں، کیونکہ واسطہ تو ڈاکٹر حضرات سے ہی پڑے گا اور وہ دیسی دوا دیکھ کر ناراض ہوں جائیں گے۔
میں واپس آ گیا اور رات بھر سوچتا رہا کہ انھوں نے یہ دوا نہ کھائی تو ساری زندگی چارپائی سے نہ اٹھ سکیں گے۔ اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی۔ دوسرے دن میں پھر گیا اور ان سے کہا کہ میری دوا بہت قیمتی ہے۔ آپ مجھے کم از کم تیس سال سے جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح اور کن حالات میں طب اسلامی پڑھی ہے۔ میں نے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ انھوں نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری پر دے سکتے ہیں تو دے دیں۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو کیپسول وہ کھا رہے ہیں، وہ سارے لا کر مجھے دے دیں۔ وہ لے آئے۔ میں نے سب کو خالی کر کے ایک کالی مرچ کے برابر ہر کیپسول میں خالص ہیرا ہینگ بھر دی۔ میں نے کہا کہ ایک کیپسول ابھی سادہ پانی سے دے دیں۔ میں نے رات وہیں گزارنے کی خواہش ظاہر کی جس سے ان کا حوصلہ بڑھا۔ سات دن صبح شام کھانے کے بعد صرف ہینگ دی گئی۔ ساتویں روز مولانا منظور صاحب پیدل چل کر اچھرہ سے نیلا گنبد آئے بھی اور گئے بھی۔ پھر وہ جتنا عرصہ زندہ رہے، سواری استعمال نہ کی۔ میں نے ان کے بھائی صاحب سے کہہ دیا تھاکہ میرا ذکر نہ کریں کہ ہر کوئی میرے پیچھے لگ جائے گا اور جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔
مولانا کو تکلیف کیا تھی؟ بظاہر ان کا ایک قدم معمولی سے ڈگمگاتا تھا، مگر کوئی یہ نہ جان سکا کہ انھیں فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ہینگ اور کالی زیری دونوں بڑے نام اور کام کی ادویہ ہیں۔ فالج کے علاوہ میں نے ہینگ کے ساتھ بڑے اونچے اور پڑھے لکھے گھرانوں کے مریضوں کا لقوہ کا علاج کیا ہے۔ آج جتنی ٹھنڈک ہمارے گھروں میں مستعمل ہے، اس نے لوگوں کو جیتے جی گڑھوں میں دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ ٹھنڈا پانی، ایئر کنڈیشنر، برف، قلفی، ٹھنڈی بوتلیں، سب زہر قاتل ہیں۔ ان سے بچیں۔
نوٹ: ہر آدمی یہ نسخہ استعمال نہ کرے، خصوصاً وہ مریض جو بلڈ پریشر یا خونی امراض کا شکار ہوں۔