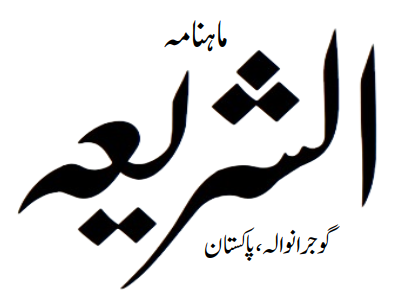جنوری ۲۰۰۱ء
حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ پر ایک نظر
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
حکومت نے آخر کار "حمود الرحمن کمیشن" کی رپورٹ کا ایک اہم حصہ عوام کی معلومات کے لیے کیبنٹ ڈویژن کی لائبریری میں رکھ دیا ہے اور اس کے اقتباسات قومی اخبارات میں شائع ہونا شروع ہوگئے ہیں۔ ۱۹۷۱ء میں ملک سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد مغربی پاکستان کے باقی ماندہ حصے میں قائم ہونے والی بھٹو حکومت نے عوامی مطالبہ پر اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سربراہ جسٹس حمود الرحمن مرحوم کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کیا تھا جس میں پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس انوا ر الحق مرحوم اور سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کے سربراہ جسٹس طفیل علی عبد الرحمن مرحوم بھی شامل تھے۔ کمیشن کے ذمہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب و عوامل کی نشاندہی اور اس کے ذمہ دار افراد کے تعین کے ساتھ ساتھ اس سلسلہ میں ضروری کارروائی کے لیے سفارشات اور تجاویز پیش کرنا تھا۔
کمیشن نے دو سو سے زیادہ افراد کے بیانات اور ستر کے لگ بھگ شہادتیں قلمبند کرنے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کر دی تھی جو "ٹاپ سیکرٹ" قرار دے دی گئی اور ملک کے عوام کو اس کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکا۔ مختلف حلقوں کی طرف سے اس رپورٹ کی اشاعت کا مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا۔ مگر اس رپورٹ کے بعد ملک میں قائم ہونے والی کسی حکومت نے بھی اس مطالبہ پر توجہ نہ دی حتی کہ اس رپورٹ کے کچھ حصے مبینہ طور پر چوری ہوئے اور بھارت کے بعض اخبارات نے گزشتہ دنوں انہیں شائع کر دیا جس پر اس رپورٹ کی اشاعت کا مطالبہ ایک بار پھر منظر عام پر آیا اور وزیر داخلہ جناب معین الدین حیدر کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے رپورٹ کا از سر نو جائزہ لے کر اس کے ایک حصے کی اشاعت کی سفارش کر دی جس پر اسے کیبنٹ ڈویژن کی لائبریری میں عوام کے مطالعہ کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔
اخباری اطلاعات کے مطابق رپورٹ کے آٹھ حصوں میں سے صرف دو حصے "اوپن" کیے گئے ہیں جبکہ باقی چھ حصے بدستور " صیغہ راز" میں ہیں اور اس کے مندرجات کو خارجہ تعلقات کے "حساس امور" قرار دے کر حسب سابق ناقابل اشاعت کے زمرے میں رکھا گیا ہے تاہم جو حصہ شائع ہوا ہے وہ بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اور اس نے ان تمام شبہات ‘ خدشات اور الزامات کی تصدیق کر دی ہے جو اس عظیم سانحہ کے حوالہ سے اس وقت کی فوجی و سیاسی قیادت اور نوکر شاہی کے بارے میں عوامی حلقوں میں وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں۔
روزنامہ جنگ لاہور ‘ نوائے وقت لاہور اور اوصاف اسلام آباد نے ۳۱ دسمبر ۲۰۰۰ء کے شماروں میں حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کی جو تفصیلات شائع کی ہیں ان میں سے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔
- جنرل یحییٰ خان‘ جنرل عبد الحمید خان‘ جنرل پیرزادہ‘ جنرل مٹھا اور ان کے رفقاء نے ۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو صدر محمد ایوب خان مرحوم کو اقتدار سے ہٹانے کی سازش کی جس پر ان کے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔
- جنرل یحییٰ خان سمیت ۱۵ اعلیٰ فوجی افسران اپنی نا اہلی‘ کرپشن‘ بد عنوانی اور بدکرداری کی وجہ سے تقسیم ملک کے ذمہ دار ہیں‘ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔
- ان فوجی افسران نے اپنے مشترکہ مفاد کی خاطر سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈالنے اور انہیں دھمکانے کے علاوہ روپے پیسے کا لالچ دے کر انتخابات کے نتائج اپنے حق میں کرانے کی کوشش کی۔
- پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے منتخب اسمبلی میں عوامی لیگ کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کی بجائے ڈھاکہ میں ۳ مارچ کو بلائے جانے والے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جانے والے ارکان اسمبلی کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی دے کر انتہائی غیر جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔
- مسٹر بھٹو نے دو اکثریتی جماعتوں کی تھیوری اور "گرینڈ کولیشن" کی تجویز پاکستان کے وفاق کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ کنفیڈریشن کے لیے پیش کی۔
- لیفٹیننٹ جنرل عمر نے سیاسی جماعتوں کو قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلانے کی مخالفت کرنے پر اکسایا۔
- ڈھاکہ میں بلایا جانے والا قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ عرصہ کے لیے ملتوی کرنے پر عوامی لیگ نے سول نا فرمانی شروع کر دی جو اس قدر بھرپور تھی کہ جنرل ٹکا خان مشرقی پاکستان کا گورنرمقرر ہو کر ڈھاکہ پہنچے تو انہیں حلف اٹھانے کے لیے کوئی جج میسر نہیں تھا۔
- یحییٰ خان نے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمن پر دباؤ ڈالا کہ وہ دستور سازی اور چھ نکات کو نظر انداز کر کے حکومت سازی میں پیپلز پارٹی سے تعاون کریں۔
- شیخ مجیب الرحمن واجبی سطح کے لیڈر تھے‘ چھ نکات ان کے مرتب کردہ نہیں تھے اور نہ ہی ان میں اتنی اہلیت و صلاحیت تھی بلکہ یہ چھ نکات جو ملک کے سب سے بڑے سیاسی تنازعہ کی بنیاد بنے مشرقی پاکستان کے ینگ سی ایس پی افسران کے ایک گروپ نے مرتب کیے تھے اور انہیں بیرونی عوامل کی پشت پناہی حاصل تھی جنہوں نے ان چھ نکات کی تشہیر اور مشرقی پاکستان کے عوام کو ان کے حق میں تیار اور متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
- تین مارچ کو ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے احتجاجی جلسہ پر فوج کی فائرنگ سے ہزاروں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ۔
- ۲۵ مارچ کو فوج نے ڈھاکہ میں آدھی رات کو پوزیشن سنبھال کر فوجی ایکشن شروع کیا جس کے نتیجے میں پچاس ہزار کے لگ بھگ افراد جاں بحق ہوئے۔
- جنرل یحییٰ خان اور ان کے ساتھی جرنیلوں کا اکثر وقت عورت اور شراب کے ساتھ مصروف گزرتا تھا اور اس مقصد کے لیے راولپنڈی صدر میں صدر یحییٰ خان کا ذاتی بنگلہ بدکاری کا اڈہ بن گیا تھا۔
- رپورٹ میں ایک درجن سے زائد عورتوں کی فہرست اور کوائف دیے گئے ہیں جن کے شب و روز یحییٰ خان اور ان کے ساتھی جرنیلوں کے ساتھ گزرتے تھے اور وہ دوسری عورتیں بھی سپلائی کرتی تھیں۔
- یحییٰ خان اکثر اوقات رات سات آٹھ بجے ڈنر کے بہانے ایوان صدر سے نکلتے اور صبح واپس آتے۔
- صدر یحییٰ خان نے صدارتی آفس میں جانا بھی ترک کر رکھا تھا اور بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران جی ایچ کیو کے آپریشن روم میں وہ صرف دو تین بار گئے۔
- نومبر ۷۱ء میں عین حالت جنگ کے دوران یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس لاہور میں تین روز ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ بسر کیے۔
- جنرل نیازی پان سمگل کرتے تھے‘ رشوت لیتے تھے اور رقاصاؤں کے گھروں میں جاتے تھے۔
- بریگیڈیر حیات اللہ نے مقبول پورکے محاذ جنگ میں عورتیں بنکرز اور مورچوں میں طلب کر لیں۔
- بریگیڈیر جہاں زیب ارباب نیشنل بینک کی سراج گنج شاخ سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے لوٹنے کی واردات میں اپنے دوسرے چھ فوجی افسر ساتھیوں سمیت ملوث ہیں۔
- جی ایچ کیو نے جنرل نیازی کو بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ فیصلہ جنرل نیازی کا ذاتی تھا۔
یہ ہے وہ ایک ہلکا سا خاکہ اس پس منظر کا جو مملکت خداداد پاکستان کے دو حصوں میں بٹ جانے اور سقوط ڈھاکہ جیسے عظیم ملی سانحہ کا باعث بنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اور ۷۱ء کے بعد ربع صدی سے زائد عرصہ میں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے‘ اس طرح کے اسباب و عوامل کو روکنے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے "جرم" اور "مجرم" دونوں پر پردہ ڈال کر خود کو اندرونی و بیرونی سازشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور حالات کی اصلاح کے لیے سقوط ڈھاکہ جیسے کسی اور سانحہ کا انتظار کر رہے ہیں؟
نعمتوں کی ناشکری پر عذاب الٰہی کا ضابطہ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
عید الفطر کے موقع پر مرکزی عید گاہ اہل سنت گوجرانوالہ میں مدیر "الشریعۃ" کا خطاب ۔
بعد الحمد والصلوٰۃ آج عید کا دن ہے‘ عید خوشی کو کہتے ہیں اور آج دنیا بھر کے مسلمان اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشی اور تشکر کا اظہار کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب ہوا اور اس میں ہر مسلمان کو اپنے ذوق اور توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نیک اعمال کا موقع ملا۔ روزہ‘ قرآن کریم کا سننا سنانا ‘ صدقہ خیرات اور نوافل کی توفیق ہوئی‘ اس خوشی میں مسلمان بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہیں اور تشکر و امتنان کا اظہار کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں ۔ قرآن کریم میں سور ۃ ابراھیم کی آیت ۷ میں ارشاد خداوندی ہے کہ
"اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر نا شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔"
یعنی جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح نا شکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اور سزا بھی دی جاتی ہے۔اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور ضابطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جونعمتیں خود انسانوں کی فرمائش پر انہیں دی جاتی ہیں‘ ان کی ناشکری پر عذاب بھی سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ میں نے آج خطبہ کے بعد سورۃ المائدۃ کی جو آیات کریمہ (۱۱۲ تا ۱۱۵) آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اسی ضابطہ اور قانون کی وضاحت کی ہے اور ایک تاریخی واقعہ کا تذکرہ کیا ہے‘ سورۃ المائدۃ اسی واقعہ سے منسوب ہے۔ مائدۃ دستر خوان کو کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اترنے کا واقعہ اس سورہ میں بیان ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سورۃ کو "المائدۃ" کہا جاتا ہے‘ وہ واقعہ انہی آیات میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ
" اور جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں گے جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا اور ہم یہ جان لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر خوان اتار دے۔ وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوگی اور آپ کی قدرت کی نشانی ہوگی‘ آپ ہمیں رزق عطا فرمادیں کیونکہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر خوان اتار دوں گا مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے نا شکری کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب اس کائنات میں اور کسی کو نہیں دوں گا۔"
یعنی جس نعمت کی فرمائش کی جا رہی ہے اس کے ملنے کے بعد بھی اگر نا شکری کی گئی تو اس پر خدا کا عذاب بہت زیادہ سخت اور بے مثال ہوگا اور اس کی سنگینی اور شدت دوسرے عذابوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔
ان آیات کے ضمن میں امام ابن جریر طبریؒ نے "تفسیر طبری" میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی ؒ نے " تفسیر مظہری" میں حکیم ترمذیؒ کی "نوادر الاصول " کے حوالہ سے حضرت سلمان فارسیؓ کی تفصیلی روایات نقل کی ہیں‘ ان دونوں کو سامنے رکھ کر واقعہ کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
ان روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جب روزہ رکھنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم ایک ماہ کے روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک ماہ مسلسل روزے رکھے اور جب تیس روزے مکمل ہوگئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم ایک ماہ تک کسی کے ہاں مزدوری اور کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طرف سے کھانا کھلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں تنبیہ کی کہ خدا سے ڈرو ‘ اس قسم کے سوالات مناسب نہیں لیکن جب وہ اپنے سوال پر قائم رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوان اتارنے کی درخواست کر دی جس پر اللہ رب العزت نے خوان اتارنے کا وعدہ کرلیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی نا شکری کی تو پھر میرا عذاب ایسا ہوگا کہ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ آسمان سے تیار کھانوں کا دستر خوان اترا بلکہ مسلسل چالیس دن تک اترتا رہا اور بنی اسرائیل سب کے سب روزانہ اس سے کھاتے رہے۔ چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی اور حکم ہو اکہ آج کے بعد یہ خوان غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہوگا اور امیر اور صاحب استطاعت افراد کو اس سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل یہ شرط بھی لگائی گئی تھی کہ دستر خوان پر بیٹھ کر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ مگر ساتھ لے جانے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور دستر خوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے کو خیانت شمار کیا جائے گا۔ مگر امیر لوگ اور صاحب استطاعت افراد ان شرائط کی پابندی نہ کر سکے اور طرح طرح کے حیلے نکال کر خلاف ورزی شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ خوان اترنا بند ہوگیا اور خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو بے فکری کے ساتھ اپنے بستروں پر محو خواب تھے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں اور انہیں خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ صبح اٹھے تو عجیب صورت حال تھی ۔ دھڑ اور جسم انسانوں کے تھے مگر چہرے اور شکلیں خنزیروں کی بن چکی تھیں۔ بنی اسرائیل میں کہرام مچ گیا‘ سب لوگ حضرت عیسٰی علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر آہ و زاری کرنے لگے۔ وہ سینکڑوں خنزیر نما انسان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کا نام لے کر پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا مگر گفتگو کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ ان کا رونا دھونا بعد از وقت تھا اس لیے کسی کام نہ آیا اور وہ خنزیر نما سینکڑوں انسان تین دن اس حال میں رہنے کے بعد موت کا شکار ہوگئے ۔ ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا اور نہ ہی کسی کی نسل آگے چلی۔
گویا اس واقعہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کا عملی اظہار فرما دیا کہ وہ عام نعمتوں کی ناشکری پر بھی سزا دیتے ہیں لیکن جو نعمت فرمائش اور درخواست کر کے لی جائے اس کی ناشکری پر ان کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔
اس حوالہ سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد گرامی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ واقعہ بیان کر کے عربوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا ۔ "تفسیر ابن کثیرؒ " میں انہی آیات کریمہ کے ضمن میں منقول ہے کہ حضرت عمار بن یاسرؐ نے ایک مجلس میں "مائدہ" والا یہ واقعہ بیان فرمایا اور پھر کہا کہ اے اہل عرب ! تم پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ حضرت محمد ﷺ جیسے عظیم پیغمبر تمہیں عطا فرمائے۔ حالانکہ ان سے پہلے تم صرف اونٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی برکت سے تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت مل گئی اور نبی اکرم ﷺ نے تمہیں ہدایت کی کہ سونا چاندی ذخیرہ نہ کرنا یعنی دولت کو جمع کرنے کے بجائے اسے مستحقین پر خرچ کرتے رہنا مگر تم نے دولت کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ تم بھی اسی طرح خدا کے عذاب کا شکار ہوگے جس طرح مائدہ والے بنی اسرائیل خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔
حضرت عمار بن یاسرؓ نے یہ بات اپنے دورکے پس منظر اور حالات میں کہی تھی لیکن آج کے حالات اور تناظر میں ان کے اس ارشاد گرامی کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح حرف بہ حرف صادق آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ پون صدی میں عربوں کو تیل اور سونے کی صورت میں جس دولت سے مالا مال کیا‘ اس کی مثال نہیں ملتی لیکن یہ دولت کہاں خرچ ہوئی؟ یہ دولت ملت اسلامیہ کے اجتماعی اور ملی مفاد میں خرچ ہوتی تو اس کا میدان سائنس‘ ٹیکنالوجی‘ دفاع اور معیشت تھا مگر عربوں کی دولت ان معاملات میں مسلمانوں کے کسی کام نہ آئی اور نہ ہی غریب مسلمانوں اور نادار لوگوں کی ضروریات پر یہ دولت صرف کی گئی البتہ عیاشی پر‘ اللّوں تللّوں پر‘ بیکار بلڈنگوں پر اور شاہانہ اخراجات پر تیل کی دولت برباد ہوگئی اور جو دولت ان کاموں پر صرف نہ ہو سکی وہ مغربی ملکوں کے بینکوں میں ذخیرہ کر دی گئی ہے جو مسلمانوں کے بجائے ان کے دشمنوں کے تصرف میں ہے اور ان کے کام آرہی ہے۔
اللہ نے چھپر پھاڑ کر عربوں کو دولت دی تھی‘ زمین کا سینہ ان کے لیے چاک کر دیا تھا مگر انہوں نے اس عظیم نعمت کی جو ناشکری کی‘ اس کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں اور اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک کے سامنے تمام عرب ممالک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ نعمتیں بھی بے حساب دیتا ہے مگر ان کی ناشکری پر اس کی گرفت بھی بڑی سخت اور عبرتناک ہوتی ہے۔ عربوں کو ایک طرف رکھئے خود ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے یعنی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے " پاکستان" جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی تھی اور یہ کہا تھاکہ یا اللہ ! اس خطہ کے مسلمانوں کو الگ ملک عطا فرما دے‘ ہم اس میں تیرے احکام کی پابندی کا اہتمام کریں گے‘ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن شریف اور دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف تھی اور ہم نے لاکھوں کے اجتماع میں عہد کیا تھا کہ پاکستان بن گیا تو ان دو کتابوں کی حکمرانی قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ ملک دے دیا اور پاکستان بن گیا مگر ہم نے کیا کیا؟ اور نصف صدی سے مسلسل کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے مملکت خداداد پاکستان کو لوٹ کھسوٹ اور مار دھاڑ کا مرکز بنا لیا۔ ہم میں سے جس کا جتنا داؤ چلا اس نے ملک کو لوٹنے اور اس کے وسائل کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
ہم نے خدا کے قانون کو‘ اسلام کے نظام کو اور قرآن و سنت کی ہدایات کو نظر انداز کردیا اور خواہشات کی غلامی میں لگ گئے۔ آج غریب آدمی کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے‘ بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں‘کھانے کو روٹی نہیں ہے اور سر چھپانے کو مکان نہیں ہے مگر چند افراد نے اپنی تجوریوں اور بیرون ملکوں بینکوں میں دولت کے انبار لگا رکھے ہیں۔ آج مجھے اور آپ سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو عید کے روز نئے کپڑے پہنے‘ خوشبو لگائے اور بنے سنورے بیٹھے ہیں مگر ہمارے اردگرد کتنے لوگ ہیں جو آج کے دن بھی اپنے بچوں کے لیے ایک دن کی عارضی خوشیوں کا اہتمام نہیں کر سکے۔ ان کی تعداد تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے او ردن بدن بڑھتی جا رہی ہے‘ ان لوگوں کا بھی وہی خدا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان لوگوں کے دلوں سے بھی آہیں نکلتی ہیں جو سیدھی عرش پر جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے‘ سبق لینا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ابھی وقت ہے اگر ہم ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سیکھا تو عذاب کا قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح اور توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین
اسلام میں عورت کا مقام
حکیم محمود احمد ظفر
اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ اس نے لاکھوں اور کروڑوں قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور اس کائنات میں اس کا دائرہ کار Function الگ الگ رکھا۔ اس دنیا میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے عورت کو بھی پیدا فرمایا اور مرد کو بھی اور دونوں کے عضوی اور احساساتی اختلافات کی وجہ سے ان دونوں کا دائرہ کار بھی الگ الگ رکھا اور عملی زندگی میں مرد کو عورت پر فوقیت دی اور فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں فرمایا: الرجال قوامون علی النساء "مرد عورتوں پر قوام ہیں"۔ عربی زبان میں قوام‘ قیام اور قیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا ہو۔ اس آیت میں قوام کا ترجمہ عموماً "حاکم" کیا جاتا ہے یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر یا حاکم ہو تاکہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے۔ جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لیے اس کی ضرورت سب کے لیے مسلم ہے‘ اسی طرح اس قبائلی نظام میں جس کو "خانہ داری " کہا جاتا ہے‘ اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے۔ عورتوں اور بچوں کے مقابلہ میں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی علمی اور عملی قوتیں بہ نسبت عورتوں اور بچوں کے زیادہ ہیں۔ اور یہ ایسا بدیہی معاملہ ہے کہ سمجھدار عورت یا مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۳۹۶)
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ؒ نے اس بارہ میں فرمایا کہ
"خلاصہ یہ کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم اور نگران حال بنایا ہے دو وجہ سے : اول بڑی اور وہبی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر یعنی مردوں کوعورتوں پر علم و عمل میں کہ جن دونوں پر تمام کمالات کا دارومدار ہے‘ فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی جس کی تشریح احادیث میں موجود ہے۔ " (فوائد عثمانی)
مردوں کو عورتوں پر فکری اور ذہنی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے‘ اسی وجہ سے انہیں عورتوں پر قوام بنایا گیا۔ یہ کون سی فکری اور ذہنی صلاحیتیں ہیں‘ ان پر بحث کرتے ہوئے اکمل الدین الباہری قدس سرہ نے عنایہ شرح ہدایہ میں فرمایا کہ :
"نفس انسانی کی قوتوں کو چار درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا درجہ کہ مطلقاً سوچنے سمجھنے کی استعداد موجود ہو۔ یہ استعداد فطرتاً ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جزئیات میں حواس کے استعمال سے بدیہی باتیں دریافت ہونے لگیں (جیسا کہ دیکھ کر رنگ کا پتہ چل جانا اور چکھ کر ذائقہ کا علم ہوجانا وغیرہ وغیرہ) اور عقل اس قابل ہو کہ اس میں غور و فکر کے ذریعہ خاص حقائق کا اکتساب کرنے لگے۔ اس کو اصطلاح میں "عقل بالملکہ" کہتے ہیں۔ اس صلاحیت کے بعد آدمی پر شریعت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بدیہی حقیقتوں سے جو نظریات مستنبط ہو رہے ہیں ان کے ادراک میں کسی قسم کی دقت اور محنت پیش نہ آئے ‘ اسکا نام "عقل بالفعل" ہے۔چوتھا درجہ یہ ہے کہ نظریات ہمیشہ ذہن میں اسطرح مستحضر رہیں گویا آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اسکو "عقل" مستفاد کہا جاتا ہے ۔"
اس کے بعد علامہ اکمل الدینؒ فرماتے ہیں :
"شریعت کی ذمہ داریوں کا دارومدار جس صلاحیت عقل پر ہے یعنی "عقل بالملکہ" عورتوں میں اس کی کمی نہیں‘ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جزئیات میں حواس کو استعمال کر کے بدیہات کو پا لیتی ہیں۔ اور اگر کسی بات کو بھول جائیں تو یاد دہانی کے بعد ذہن میں حاضر بھی کر لیتی ہیں۔ اگر ان کی صلاحیت میں کسی قسم کا نقص ہوتا تو دین کے جن ارکان کی ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی گئی گئی ہیں‘ عورتوں کو اس سے مختلف ارکان کی تکلیف دی جاتی‘ حالانکہ صورت واقعہ یہ نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو ان کے بارہ میں "ناقصات عقل" فرمایا ہے تو اس سے "عقل بالفعل" مراد ہے۔" (عنایہ علیٰ فتح القدیر ج ۶ ص ۸)
معلوم ہوا کہ وہ عقل جس سے بدیہی حقیقتوں سے جو نظریات مستنبط ہو رہے ہیں ان کے ادراک میں کسی قسم کی دقت اور محنت پیش نہ آئے‘ اس عقل میں عورت کمزور اور ناقص ہے۔ یہ علامہ اکمل الدین کی تحقیق ہے جو قرآنی اصول کو ثابت کرتی ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔
"مرد عورتوں پر قوام ہیں" قرآن حکیم کی اس بات کو وضعی قانون نے غلط قرار دیا‘ لیکن گزشتہ سو سالہ تجربہ اور تحقیق نے بتایا کہ الٰہی قانون ہی اس معاملہ میں حقیقت سے قریب تر ہے۔ آزادی نسواں کی تحریک کی تمام تر کامیابیوں کے باوجود آج بھی نام نہاد "مہذب دنیا" میں مرد ہی جنس برتر Dominant Sex کی حیثیت رکھتے ہیں۔
آزادی نسواں کی تحریک کے علم برداروں کی سب سے بڑی دلیل اس سلسلہ میں یہ تھی کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی فطری فرق نہیں بلکہ سماجی فرق ہے۔ اگر عورت پر سماجی دباؤ ختم کر دیا جائے تو وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے اور عورت کسی لحاظ سے مرد سے پیچھے نہیں رہے گی۔
اس تحریک کو دو سو سال سے اوپر ہوگئے ہیں اور ان ملکوں میں یہ تحریک پوری طرح کامیاب بھی ہو چکی ہے جو صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ ہیں۔ ان ملکوں میں عورت اور مرد کی برابری کے قوانین بھی بنائے جا چکے ہیں مگر قانون یا رواج اور سماج کے لحاظ سے آج کی عورت اب بھی وہاں کے مرد سے بہت پیچھے ہے‘ اور زندگی کے ہر شعبہ میں مرد کی برابری نہیں کر سکی ہے۔
یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ یورپ اور امریکہ کا ہر مفکر‘ دانشور اور مبصر اس کا اعتراف کرتا ہے۔ چنانچہ علمی دنیا کی نہایت معتبر کتاب انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے لکھا ہے :
"اقتصادی میدان میں گھر سے باہر کام کرنے والی عورتیں بہت زیادہ تعداد میں کم تنخواہ پانے والے کاموں میں ہیں۔ اور ان کا درجہ (status) سب سے کم اور نیچا ہے ۔ حتی کہ عورتیں ہر اس کام میں جو عورتیں اور مرد دونوں کرتے ہیں‘ کم تنخواہ پاتی ہیں۔ ۱۹۸۲ء میں ایک عام عورت کی تنخواہ امریکہ میں مرد کی تنخواہ کے ۶۰ فیصد کے برابر تھی۔ اور جاپان میں اوسطاً ۵۵ فیصد ۔ سیاسی لحاظ سے بھی سیاسی جماعتوں اور لوکل اور مرکزی حکومتوں میں زیادہ عورتیں مردوں سے نیچی ہیں"
اس سے معلوم ہوا کہ حکماء مغرب نے آزادی نسواں کی تشخیص غلط کی تھی۔ ان کی تشخیص یہ تھی کہ ان دونوں صنفوں میں یہ فرق سماجی حالات کی بنا پر ہے۔ حالانکہ یہ فرق اسلام کی نشاندہی کے مطابق پیدائشی بناوٹ کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی مفکرین نے اس مسئلہ پر بڑی تحقیق کی اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جب تک ان دونوں صنفوں میں یہ عضوی اور احساساتی فرق رہے گا‘ دونوں کی سماجی حیثیت میں بھی فرق رہے گا۔
"اسلام میں عورت مرد سے کم تر ہے" یہ یورپ کا معاندانہ پراپیگنڈہ ہے جو وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آج سے نہیں بلکہ دو تین سو سال سے کرتے چلے آرہے ہیں۔ چنانچہ مشہور مستشرق ایڈورڈ ولیم لین نے اپنی کتاب Selection from Quran کے دیباچہ میں لکھا ہے :
The fatal point in Islam is the degradation of women
"اسلام میں تباہ کن پہلو عورت کو حقیر درجہ دینا ہے۔"
اسی طرح ایک اور مفکر جے ایم رابرٹس J.M. Roberts نے لکھا :
Its coming was in many ways revolutionary. It kept women, for example, in an inferior position .... (The Pelican History of the World, P.334)
"دنیا میں اسلام کی آمد کئی لحاظ سے انقلابی تھی‘ مثال کے طور پر اس نے عورت کو کم درجہ دیا۔"
اسلام میں عورت کو کم درجہ دیا گیا ہے‘ یہ در اصل اسلام کی بات کو بگاڑ کر پیش کرنا ہے۔ اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ عورت مرد سے کم تر ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ "عورت مرد سے مختلف ہے" یہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں فرق کا معاملہ ہے نہ کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کے بہتر (Better) ہونے کا۔ مرد اور عورت کے بارہ میں اسلام کے سارے قوانین اسی اصول پر مبنی ہیں کہ عورت اور مرد دو الگ الگ صنفیں ہیں‘ لہذا خاندانی اور سماجی زندگی میں ان کا دائرہ عمل بھی ایک نہیں بلکہ مختلف ہے۔ اور ایک ہو بھی نہیں سکتا ۔ کیونکہ جب دونوں صنفوں کے مابین حیاتیاتی بناوٹ کے لحاظ سے فرق ہے تو ان کے درمیان عمل کے لحاظ سے بھی لازمی طور پر فرق ہونا چاہیے۔
مرد اور عورت کے درمیان جو فرق اسلام نے بتایا ہے اس کو موجودہ دور میں علم انسانی کے ماہرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ امریکہ کے ایک پروفیسر اسٹیون گولڈ برگ نے لکھا ہے :
"اس فرق کی زیادہ حقیقت پسندانہ توجیہ یہ ہے کہ اس کو مردانہ ہارمون Male Harmone کا نتیجہ قرار دیا جائے جو کہ ابتدائی جرثومہ حیات پر اس وقت غالب آجاتے ہیں جب کہ ابھی وہ رحم مادر میں ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ چھوٹے بچے چھوٹی بچیوں سے ہمیشہ جارح ہوتے ہیں۔"
آگے چل کر پروفیسر گولڈ برگ لکھتا ہے :
"اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورتوں سے بہتر ہوتے ہیں بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مرد عورتوں سے مختلف Different ہوتے ہیں۔ مرد کا دماغ اس سے مختلف کام کرتا ہے جس طرح عورت کا دماغ کام کرتا ہے۔ یہ فرق چوہوں وغیرہ کے نر اور مادہ میں بہت زیادہ واضح طور پر تجربہ کیا جا سکتا ہے۔" (ڈیلی ایکسپریس مورخہ ۴ جولائی ۱۹۷۷ء)
یورپ کے مشہور مفکر‘ دانشور اور نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر الیکسیش کیرل نے بھی اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے اسلام کے نظریہ مرد و زن کی تائید کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس معاملہ کی حیاتیاتی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :
"مرد اور عورت کے درمیان جو فرق پائے جاتے ہیں وہ محض جنسی اعضاء کی خاص شکل‘ رحم کی موجودگی‘ حمل یا طریقہ تعلیم کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ وہ اس سے زیادہ بنیادی نوعیت کے ہیں جو خود نسیجوں کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور پورے نظام میں خصوصی کیمیاوی مادے کے سرایت کرنے سے ہوتے ہیں جو کہ خصیۃ الرحم سے نکلتے ہیں۔ ان بنیادی حقیقتوں سے بے خبری اور نا واقفیت نے ترقی نسواں کے حامیوں کو اس عقیدے پر پہنچایا ہے کہ دونوں صنفوں کے لیے ایک قسم کی تعلیم‘ ایک طرح کے اختیارات اور ایک طرح کی ذمہ داریاں ہونی چاہئیں۔"
ڈاکٹرصاحب اس سلسلہ میں مزید لکھتے ہیں :
" حقیقت کے اعتبار سے عورت نہایت گہرے طور پر مرد سے مختلف ہے۔ عورت کے جسم کے ہر خلیہ میں زنانہ پن کا اثر موجود ہوتا ہے۔ یہی بات اس کے اعضا کے بارہ میں صحیح اور درست ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کے اعصابی نظام کے بارہ میں عضویاتی قوانین بھی اتنے ہی اٹل ہیں جتنا فلکیاتی قوانین قطعی اور اٹل ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ انہیں اسی طرح مانیں جیسے وہ ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو خود اپنی فطرت کے مطابق ترقی دیں۔ وہ مردوں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تہذیب کی ترقی میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ مردوں کا ہے۔ انہیں اپنے مخصوص عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔"
(Dr. Alexis Carel : Man the unknown, New Yrok. P. 91)
انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کی 19 ویں جلد میں خواتین کا درجہ Status of Women پر ایک مفصل مقالہ لکھا گیا ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان پیدائشی بناوٹ کے لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے۔ مقالہ نگار لکھتا ہے:
"اوصاف شخصیت کے لحاظ سے مردوں کے اندر جارحیت اور غلبہ کی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ ان میں حاصل کرنے کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں عورتیں کوئی سہارا چاہتی ہیں۔ ان کے اندر معاشرہ پسندی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اور ناکامی کی صورت میں مردوں کے مقابلے وہ زیادہ آسانی سے بے ہمت ہو جاتی ہیں۔"
آزادی نسواں کے علم بردار یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا فرق محض سماجی حالات کی پیداوار ہے مگر موجودہ زمانہ میں مختلف متعلقہ شعبوں میں اس مسئلہ کا جو گہرا مطالعہ کیا گیا ہے‘ اس سے ثابت ہوا ہے کہ صنفی فرق کے پیچھے حیاتیاتی عوامل Biological Factors کار فرما ہیں۔ ایک امریکی سرجن Edgar Berman کا فیصلہ ہے کہ عورتیں اپنی ہارمون کیمسٹری کی وجہ سے اقتدار کے منصب کے لیے جذباتی ثابت ہو سکتی ہیں۔
Because of their hormonal chemistry, women might be too emotional for position of power. (Time Magazine, March 20 , 1972, P 28)
امریکہ میں آزادی نسواں کی تحریک کافی طاقت ور ہے‘ لیکن اب اس کے حامی محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کی راہ کی اصل رکاوٹ سماج یا قانون نہیں بلکہ خود فطرت ہے۔ فطری طور پر ہی ایسا ہے کہ عورت بعض حیاتیاتی محدودیت Limitations of Biology کا شکار ہے۔ میل ہارمون اور فی میل ہارمون Male & Female Harmone کا فرق دونوں میں زندگی کے آغاز ہی سے موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ تحریک آزادی نسواں کے پرجوش حامی کہنے لگے ہیں کہ فطرت ظالم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پیدائشی سائنس Science of Exergies کے ذریعے نئے قسم کے مرد اور نئی قسم کی عورتیں پیدا کریں۔
یورپ ‘ امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی عورت مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے اور مردوں کی طرح کمانے اور خود کفیل ہونے کے لیے باہر نکلی تو اس کو معلوم ہوگیا کہ بعض حیاتیاتی اور فطری کمزوریوں کی وجہ سے کسی شعبہ زندگی میں بھی وہ مردوں کے برابر کام نہیں کر سکتی تو اس نے اپنے نسوانی جسم کا سودا کرنے کے لیے اس کو سربازار لٹکا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو مرد کی برابری کا درجہ تو نہ ملا البتہ معاشرہ طرح طرح کے مسائل سے دو چار ہوگیا جن میں عریانیت ‘ جنسی جرائم‘ بے نکاحی زندگی اور بغیر والد کے بچے سرفہرست ہیں۔
افسوس یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ آزادی نسواں کی جس تحریک سے اب تنگ آچکے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عورت کسی میدان میں بھی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی‘ اس تحریک کو اب پاکستان میں بعض مخصوص نہج کی عورتیں اپنی لیڈری چمکانے کے لیے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ پاکستان کی پاک باز اور با عصمت عورت کو چراغ خانہ کے بجائے شمع انجمن بنانا چاہتی ہیں۔ اکبر الٰہ آبادی نے سچ کہا تھا
حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی
اب ہے شمع انجمن‘ پہلے چراغ خانہ تھی
جو غلطی یورپ اور امریکہ نے دو سو برس قبل کی تھی کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی فطری فرق نہیں بلکہ سماجی فرق ہے‘ وہی غلطی آج پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ یاد رکھئے عورت مرد سے مختلف ہے‘ لہذا اس کا دائرہ کار بھی مختلف ہے۔ یہی اسلام کا فیصلہ ہے اور یہی فیصلہ یورپ اور امریکہ کے دانشوروں اور مفکرین کا ہے۔
تحریک ریشمی رومال پر ایک نظر
مولانا شمس الحق مشتاق
یہ بیسویں صدی کا حیدر آباد سندھ ہے۔ قدیم طرز کے مکان میں ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس سوئی دھاگا لیے ایک زرد رنگ کا رومال جس کی لمبائی ایک گز ہے اور عرض بھی اتنا ہی ہے گدڑی میں سی رہا ہے۔ وضع قطع اور صورت شکل سے درویش نظر آتا ہے۔ اچانک ایک دھماکہ سا ہوتا ہے وہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے چند گورے اور سکھ فوجی صحن کی دیواریں پھاند کر اس کی طرف لپکے آرہے ہیں۔ وہ گدڑی اٹھا کر کمرے کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن فوجی سر پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سے گدڑی چھین لیتے ہیں۔ وہ شخص ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور صحن میں پہنچ کر دیوار پھاند لیتا ہے۔ چند فوجی اس کے پیچھے جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ہاتھ ملتے لوٹ آتے ہیں۔
یہ درویش آزادی ہند کی انقلابی پارٹی کے سرگرم اور سرفروش رکن اور پارٹی کے قائد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ کے قابل اعتماد پیروکار شیخ عبد الرحیم تھے۔ اچاریہ کرپلانی کے حقیقی بھائی جو مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے ہاتھ پر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔
پارٹی کا مرکزی دفتر پہلے دیوبند میں تھا بعد میں دہلی منتقل ہوگیا۔ تحریک کا نام جس کی بنا پر پارٹی تشکیل دی گئی تھی پہلے ثمرۃ التربیہ اور پھر جمعیۃ الانصار رکھا گیا تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ ہندوستان پر قابض انگریز حکومت کے خلاف ملک بھر میں عام بغاوت کرائی جائے اس طرح ملک کو فرنگی استبداد سے آزاد کرانا تھا۔ منصوبے کے مطابق ترکی کی فوج کو افغانستان کے راستے حملہ آور ہونا تھا اس لیے افغانستان کی حکومت کو بھی جس کا سربراہ حبیب اللہ خان تھا ہموار کرنا تھا ۔ ترکی سے یہ طے کیا جا رہا تھا کہ اس کی فوج ہندوستان کو آزاد کراکے لوٹ جائے گی ۔ اس مدد کے عوض آزاد ہندوستان اس کی اخلاقی اور مالی امداد کرتا رہے گا۔ ترکی فوج کے کماندار غازی انور پاشا تھے۔
اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے دس جامع منصوبے ۱۹۰۵ء میں بنائے گئے تھے۔ ان کی تکمیل ۱۹۱۴ء میں ہوئی۔ منصوبے یہ تھے : ہندو مسلم مکمل اتحاد‘ علماء فکر قدیم اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اشتراک فکر و عمل‘ اقوام عالم سے اخلاقی مدد کا حصول‘ جنگی نقشوں کی تیاری‘ انقلاب کے بعد عبوری حکومت کے خاکے کی ترتیب‘ بغاوت کے خفیہ مراکز کا قیام‘ بیرون ملک امدادی مراکز کا تعین‘ ترکی کی حمایت کے لیے دوسرے ملکوں سے رابطہ ‘ باہر سے حملے کے لیے راستوں کی نشاندہی‘ بیک وقت بغاوت اور حملے کے لیے تاریخ کا تعین۔
تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے معرکہ بالا کوٹ ۱۸۳۱ء اور انقلاب ۱۸۵۷ء کی خونچکاں اقدامات کے بعد یہ تیسری سرفروشانہ تحریک تھی جو تحریک ریشمی رومال کے نام سے تاریخ کے صفحوں پر انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ پہلی تحریک مسلمانوں کے جاہلانہ تغافل سے ناکام ہوئی۔ لیکن دوسری اور تیسری تحریکیں بعض لوگوں کے مجرمانہ عدم تعاون اور کھلے بندوں غداری سے ملیا میٹ ہوئیں۔ یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ تینوں تحریکوں میں بنیادی اور مرکزی کردار علمائے حق نے ادا کیا ۔ انقلاب ۱۸۵۷ء میں عام مسلمانوں کا زیادہ حصہ ہے لیکن دوسری دونوں تحریکوں کا سہرا تمام تر علماء حق کے سر ہے۔ تحریک ریشمی رومال کی کامیابی اپنوں کی غداری اور انگریزوں کے طے شدہ حفظ ما تقدم کے باوجود یقینی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بیرونی امداد کے امکانات دسترس میں تھے۔ ۱۸۵۸ء میں سامراجیت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے براہ راست حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں منتقلی کے بعد انگریز دشمنی کے دور کا آغاز ہو چلا تھا ۔ بعید نہ تھا کہ یہ خارجی نیک فال داخلی جدوجہد کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی۔ برطانیہ کی توسیع پسندی کے پیش نظر ۱۸۵۰ء میں دوار آف بھوٹان پر قبضہ کیا گیا اور برما کے شمالی حصہ کو فتح کر کے سلطنت میں شامل کیا گیا۔ ۱۸۶۸ء میں تبت اور چین پر حملہ کیا گیا اور سرحد کے مجاہدین پر فوج کشی ہوئی۔ ۱۸۸۵ء میں کابل پر حملہ کیا گیا۔ ۱۸۹۰ء میں حکومت منی پور پر تسلط کیا گیا۔ ۱۸۹۵ء میں چترال پر قبضہ ہوا۔ ۱۸۹۶ء میں تیراہ پر حملہ کیا گیا۔ ۱۸۹۷ء میں دوبارہ سرحدی مجاہدین کے خلاف چھ مہمیں بھیجی گئیں۔ بیرونی امداد کے سلسلے میں حکومت ترکی سے توقع کسی خوش فہمی اور جذباتیت کی بنا پر نہیں تھی اس کے پس منظر میں ٹھوس حقائق اور دلائل تھے ۔ترکی برطانیہ کا زخم خوردہ تھا۔ اگر مذہب اور حریت پسندی ہندوستان اور ترکی میں قدر مشترک نہ ہوتی تب بھی سیاسی طور پر ترکی کی طرف سے مدد لازمی تھی۔ ۱۸۳۹ء میں انگریزوں نے سلطان عبد المجید خان کو محمد علی پاشا کی بغاوت کے خلاف مدد دی اور اس کے عوض میں پہلے عدن کی بندرگاہ اور پھر سارے عدن پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کی وجہ سے آنے والے برسوں میں جو نتائج نکلے وہ تصور میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس مدد کا سارا خرچ (بیس لاکھ پونڈ) ہندوستان کے ذمہ قرض کے طور پر ڈالا گیا۔ ۱۸۷۸ء میں باب عالی سلطان عبد المجید خان سے خفیہ معاہدہ کر کے جزیرہ قبرص قبضے میں کیا گیا اس کے بھی دور رس نتائج نکلے۔ اسی سال برلن میں یورپی ملکوں کی کانفرنس ہوئی جس میں ترکی کے حصے بخرے کر کے آپس میں بانٹ لیے گئے۔ برطانیہ بھی حصے دار بنا۔ ۱۸۵۸ء میں رومانیہ‘ بلغاریہ‘ کریٹ‘ سرویا‘ مولڈویا‘ ولاچیا‘ ابوسینا‘ مونٹی ‘ نیگرو اور ارضی گونیا کو ترکی کے قبضے سے نکلوا دیا۔ ۱۹۰۴ء میں برطانیہ کی شہ پر فرانس نے مراکش پر قبضہ کر لیا۔
۱۹۰۸ء میں ترکی میں فوجی انقلاب رونما ہوا۔ یہ انقلاب فوجیوں کی تنظیم " اتحاد المسلمین" نے برپا کیا تھا جس کے قائد غازی انور پاشا تھے۔ بعد میں یہی حکومت کے سربراہ بنے۔ ۱۹۱۲ء کی جنگ بلقان میں ہندوستان کی حریت پسند تحریکوں نے ترکی کی جو اخلاقی اور مالی مدد کی تھی اسے انور پاشا بھولے نہیں تھے۔ اس لیے تحریک ریشمی رومال کو ترک کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی مدد غیر متوقع نہیں تھی۔ تحریک کے پہلے دو منصوبوں کے لیے فضا پہلے ہی سازگار تھی۔ ہندوستان کے تمام حریت پسندوں میں ذہنی ہم آہنگی اور اشتراک عمل کا جذبہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے وقت ہی سے پیدا ہو چکا تھا اور اس کا مظاہرہ بار بار خصوصاً ۱۸۵۷ء میں اور اس کے بعد ہو چکا تھا۔ تحریک کے عملی قائد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن تھے لیکن اس کے قیام اور ساری منصوبہ بندی میں جن شخصیتوں کا ہاتھ تھا ان میں رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر‘ مولانا شوکت علی‘ مولانا ابوالکلام آزاد‘ مولانا عبید اللہ سندھی‘ ڈاکٹر انصاری‘ موتی لال نہرو‘ لاجپت رائے اور راجندر پرشاد شامل تھے۔ اس کے علاوہ ۱۸۵۷ء کے انقلاب نے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک کھیپ مہیا کر دی تھی جن کے دلوں میں حریت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں اور ذہن جدید طبیعاتی تقاضوں سے روشن تھے۔ ان نوجوانوں میں جن لوگوں کو اہم فرائض سونپے گئے ان میں پروفیسر برکت اللہ ایم اے تھے جنہیں ترکی‘ جرمنی اور جاپانی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ چوہدری رحمت علی گریجویٹ‘ لالہ ہرویال ایم اے‘ کامریڈ ستھرا سنگھ گریجویٹ‘ مولوی محمد علی قصوری گریجویٹ‘ میاں عبد الباری ایم اے‘ رام چندر گریجویٹ‘ بمبئی کے شیخ محمد ابراہیم ایم اے اور چینی زبان میں ماہر بنگال کے شوکت علی گریجویٹ وغیرہ شامل تھے۔ تیسرے منصوبے کے تحت چین‘ جاپان‘ فرانس‘ برما اور امریکہ میں کام شروع کیا گیا۔ اس کے لیے مشنری طریقہ کار اپنایا گیا۔ پہلا مشن دیوبند سے فارغ التحصیل مولانا مقبول الرحمن مانسہرہ ہزارہ اور شوکت علی کی سرکردگی میں چین بھیجا گیا جس میں چھ اور افراد بھی شامل تھے لیکن چین میں ایک مرکزی سیرت کمیٹی قائم کر کے ملک بھر میں اس کی شاخیں کھول دی گئیں۔ اردو اور چینی زبانوں میں ایک رسالہ "الیقین" جاری کیا گیا۔ ان کاموں میں مشن کو بڑی کامیابی ہوئی۔ چینی مسلمانوں کی خاصی تعداد ہندوستان کی صورت حال سے متاثر ہوئی اور انگریز سامراجیت سے چھٹکارا دلانے میں ہر ممکن اخلاقی مدد کا وعدہ کیا۔ ہر چند کہ چینی عوام خودظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے تھے ۔ حکومت کی سطح پر کوئی نمایاں کام نہ ہو سکا کیونکہ ملک پر سامراجیت کے دوسرے روپ شہنشاہیت اور جاگیر داری کا تسلط تھا۔ مشن نے اپنے اخراجات اس طرح پورے کیے کہ ایک شفاخانہ کھول لیا۔ مولانا مقبول الرحمن طبابت اور شوکت علی ڈاکٹری کرتے تھے۔
۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۹ء تک چین میں کام کرنے کے بعد دونوں صاحبان کو برما جانے کا حکم ملا۔ مشن کے تین ارکان کو چین میں کام کی نگرانی کے لیے چھوڑا گیا۔ شفاخانے کو فروخت کر کے ان کے گزارے کے لیے رقم دی گئی اور سفر کا خرچ بھی نکالا گیا۔ ایک آدمی کو واپس ہندوستان بھیجا گیا اور چار آدمی برما پہنچے۔ وہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا گیا جس میں کافی منافع ہوا۔ برما میں مذہبی طریقہ کار اپنانے سے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ لہذا انسانی رشتے کو مقصد کے حصول کے ذریعہ بنایا گیا اور انسانی برادری کے نام سے ایک انجمن بنائی گئی جس کا نصب العین انسانی فلاح و بہبود بتایا گیا۔ مولانا مقبول الرحمن نے عربی زبان میں ایک کتاب "الانسان" لکھی ۔ اس کا انگریزی اور برمی زبانوں میں شوکت علی نے ترجمہ کیا۔ مشن ۱۹۱۲ء تک بڑی کامیابی سے اپنا کام کرتا رہا ۔ اس نے ہزاروں افراد کو ہندوستان کی اخلاقی مدد کے لیے تیار کیا جس سے ایک مخلص حلقہ پیدا ہوگیا شومئی قسمت کہ ۱۹۱۲ء میں تحریک ناکام ہوگئی ۔ شوکت علی اور دونوں ہندو اراکین ہندوستان چلے گئے اور مولانا مقبول الرحمن رنگون جا پہنچے ۔ شوکت علی ہندوستان سے فرار ہو کر برلن چلے گئے اور مولانا مقبول الرحمن ۱۹۲۳ء میں وطن لوٹے۔
دوسرا مشن جاپان بھیجا گیا ۔ اس میں پانچ آدمی تھے اور قائد پروفیسر برکت اللہ تھے۔ انگریزی‘ ترکی‘ جرمنی زبانوں کے علاوہ جاپانی زبان میں بھی مہارت رکھنے کی وجہ سے انہیں ٹوکیو کے ایک کالج میں پروفیسری مل گئی۔ مشن نے اسلامک فریٹرنٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی اور اسی نام سے انگریزی اور جاپانی زبانوں میں رسالہ نکالا جس کے مدیر پروفیسر صاحب تھے۔ ترکی کی طرح جاپان سے بھی بھرپور مدد کی توقع تھی کیونکہ جاپان برطانیہ کا سخت مخالف تھا۔ اسی مخالفت کی بنا پر اس نے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ پر حملہ کیا تھا۔ مشن کو یہاں کامیابی سے ہمکنار ہوتا دیکھ کر ۱۹۱۰ء میں پروفیسر برکت اللہ کو چوہدری رحمت علی کی مدد کے لیے فرانس جانے کا حکم ملا۔ جہاں چوہدری صاحب کی سرکردگی میں تیسرا مشن کام کر رہا تھا۔ پروفیسر صاحب نے ملازمت چھوڑ دی ‘ اخبار بند کر دیا اور ساتھی کو لے کر فرانس کی طرف روانہ ہوگئے۔
فرانس کے مشن میں چوہدری رحمت علی کے ساتھ دو آدمی تھے‘ ان میں ایک گریجویٹ رام چندر نہایت قابل نوجوان تھا۔ پروفیسر برکت اللہ نے انگریزی زبان میں ایک اخبار "انقلاب" جاری کیا اور تندہی سے کام کرنے لگے۔ یہ اخبار مشن کی تشکیل کردہ غدر پارٹی کا ترجمان تھا۔ رولٹ کمیٹی کی رپورٹ میں اخبار کا نام بھی غدار لکھا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔ فرانس میں چھ سال تک کام ہوتا رہا۔ عوامی سطح پر "غدر پارٹی" کی بہت حوصلہ افزائی کی گئی۔ اخلاقی مدد کے بھی روشن امکانات تھے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی امید نہیں تھی۔ جو کچھ حاصل ہوا اسی پر اکتفا کر کے پروفیسر برکت اللہ اور چوہدری رحمت علی کو امریکہ جانے کا حکم ملا۔
امریکہ میں لال ہر دیال کی سربراہی میں چھ آدمیوں پر مشتمل مشن کام کر رہا تھا۔ پروفیسر صاحب اور چوہدری صاحب کی شمولیت سے تعداد آٹھ ہوگئی۔ یہاں بھی "غدر پارٹی" کام کر رہی تھی۔ ان دونوں حضرات کے آنے کے بعد پروفیسر صاحب کی ادارت میں "غدر" نام سے ایک اخبار نکالا گیا۔ در اصل واشنگٹن کے اسی اخبار کا مغالطہ رولٹ کمیٹی کو ہوا تھا۔ چوہدری رحمت علی کی سکونت تو پیرس میں تھی لیکن وہ واشنگٹن آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں کچھ زمین بھی خرید لی تھی۔ انہوں نے اسے بیچ کر ایک ہوٹل کھول لیا۔ اس کے ایک کمرے میں پارٹی کا اور دوسرے کمرے میں اخبار کا دفتر قائم کیا گیا۔ ہوٹل کی آمدنی سے اخراجات پورے ہوتے رہے اور یہ پہلے ہردیال اور چوہدری صاحب کی نگرانی میں چلتا رہا اس کے علاوہ پارٹی والوں نے رنگوں کا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ اس میں سے آمدنی بھی تھی اور دہلی کے مرکز سے رابطہ بھی قائم تھا۔ دہلی کے چار مسلمان اور تین ہندو‘ پشاور کے دو مسلمان ‘ ایک ہندو ‘ لاہور کے دو مسلمان اور پانچ ہندو‘ بمبئی کا ایک مسلمان اور چار ہندو‘ کلکتہ کے چار ہندو اور ایک مسلمان‘ ڈھاکہ کے دو ہندو ایک مسلمان اور کراچی کا ایک ہندو ان لوگوں سے مال منگواتے تھے اور کاروبار کی آڑ میں مرکز کی رپورٹیں بھیجی اور ہدایات حاصل کی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں تحریک کے ناکام ہونے کی خبر ملی تو ہوٹل فروخت کر دیا گیا اور اخبار بھی بند کر دیا گیا۔ مشن کے اراکین پیرس چلے گئے‘ وہاں سے جنیوا اور برلن ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے اور وطن آ گئے۔
انقلابیوں کا چوتھا منصوبہ جنگی نقشوں کی تیاری تھا۔ اس منصوبے کو تین شکلیں دی گئیں۔ پہلی شکل تھی بیرونی حملے کے لیے راستوں اور محاذوں کی تفصیلی نشاندہی کرنا۔ حملہ آور فوج کے لیے رسد رسانی اور اس کے اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطے اور انقلابی رضا کاروں سے رابطے کے لیے پیغام رسانی کا انتظام کرنا اور حملہ آور فوج کی نقل و حرکت کے لیے سہولت فراہم کرنا۔ دوسری شکل یہ تھی کہ سی آئی ڈی کے آدمیوں سے تعاون حاصل کیا جائے اور اس محکمے میں اپنے آدمی داخل کیے جائیں تا کہ حکومت کی پالیسیوں اور اداروں کی خبر ملتی رہے ۔ تیسری شکل تھی فوج میں اپنے ہم خیال بنانا اور انقلابی کارکنوں کو فوج میں بھرتی کرانا تا کہ جب حملہ ہو تو دشمن کو سبو تاژ کیا جا سکے۔
پہلا کام مولانا عبید اللہ سندھی کو سونپا گیا اور بمبئی کے شیخ محمد ابراہیم ایم اے کو ان کا مددگار بنایا گیا۔ مولانا نے شمال مغربی سرحد کے کئی دورے کیے۔ جغرافیائی پوزیشن کا بغور نظر معائنہ کیا۔ فنون حرب سے آگاہی کے لیے انگریزی‘ جرمنی‘ ترکی‘ فرانسیسی اور عربی زبانوں کی کتابیں منگوا کر ان کا مطالعہ کیا۔ قدیم اور جدید طریقوں کو پرکھا اور متواتر سات سال تک کام کرنے کے بعد جنگ اور اس کے محاذوں کا ایک فقید المثال نقشہ تیار کیا۔ ان کے مطالعے سے بعد میں ترکی‘ جرمنی اور افغان فوجی افسروں نے بھی استفادہ کیا۔ مولانا کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے والئی افغانستان امیر امان اللہ اور انگریزوں کے مابین جنگ میں افغان فوج کی ناقابل فراموش رہنمائی کی۔ دوسرے کام کی سربراہی ڈاکٹر انصاری نے انجام دی ۔ بہت سے ہندو اور مسلم نوجوان سی آئی ڈی میں گھس گئے اور حکومت کے راز قائدین تحریک تک پہنچاتے رہے۔ تحریک کی ناکامی کے بعد کئی نوجوان پکڑے گئے اور پھانسی پر لٹکائے گئے۔ تیسری شکل کے تحت منتخب نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرایا گیا۔ انہوں نے حب الوطن فوجیوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ بعض پکڑے بھی گئے اور کچھ لوگ تحریک کی ناکامی کے بعد بھی رہے اور پہلی جنگ عظیم کے بعد فوج سے نکل گئے۔ بعض ایسے بھی جو مستقل طور پر فوج میں رہے اور دوسری جنگ عظیم میں دوسرے افراد کو اپنے ساتھ ملا کر آزاد ہند فوج کے روپ میں سامنے آئے۔
پانچویں منصوبے کے تحت انقلاب کے بعد قائم ہونے والی عبوری حکومت کا خاکہ یہ بنایا گیا کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیارات کی کونسل ہوگی۔ مسلمان رکن کے لیے شیخ الہند مولانا محمود حسن کا نام تھا۔ ہندو رکن کا نام تحقیق طلب ہے۔ کونسل کے تحت صدر‘ وزیر اعظم‘ وزیر مملکت اور ان کے ماتحت کابینہ ہوگی۔ ان عہدے داروں کے لیے مجوزہ افراد علی الترتیب راجہ مہندر پرتاب‘ پروفیسر برکت اللہ او رمولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ انہی لوگوں نے کابینہ بنانا تھی۔ فوج کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے حضرت شیخ الہند کا نام تھا جرنیلوں کی تعداد بارہ رکھی گئی تھی۔
چھٹا منصوبہ بغاوت کے خفیہ مراکز کے قیام کا تھا۔ ہیڈ کوارٹر دہلی میں بنایا گیا ۔ اس میں شیخ الہند‘ مولانا محمد علی‘ مولانا شوکت علی‘ مولانا ابوالکلام آزاد‘ مولانا عبید اللہ سندھی‘ ڈاکٹر انصاری‘ گاندھی جی‘ پنڈت موتی لال نہرو‘ لالہ لاجپت رائے اور بابو راجندر پرشاد وغیرہ صف اول کے لوگ تھے ہیڈکوارٹر کے تحت آٹھ شاخیں پانی پت (یوپی کے اضلاع) لاہور (پنجاب) راندیر (بمبئی) گجرات کاٹھیاواڑ (مہاراشٹر) کراچی (قلات) لسبیلہ وغیرہ‘ اتمان زئی (شمالی سرحد) دین پور (بہاول پور) اور ترنگ زئی (آزاد قبائل) ‘ امروٹ (سندھ) میں کام کرتی تھیں۔ ان شاخوں کے امیر علیٰ الترتیب مولانا احمد اللہ‘ مولانا محمد احمد‘ مولانا محمد ابراہیم‘ مولانا محمد صادق‘ خان عبد الغفار خان‘ مولانا غلام محمد‘ مولانا فضل واحد اور مولانا تاج محمود تھے۔ مرکز میں ہندو اراکین کی موجودگی کے باوجود کسی شاخ کا سربراہ ہندو نہیں تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق بنگال میں بھی شاخیں تھیں۔ بنگال میں مولانا ریاض احمد اور شمال مغربی سرحد میں تین علماء کی مشترکہ کمان تھی۔ کہا جاتا ہے کہ چند سال بعد جب آزاد قبائل اور انگریزوں کی خونریز جھڑپیں ہوئیں اور انگریز فوج کو پے در پے ہزیمت اٹھانی پڑی تو یہ اسی کام کا کارنامہ تھا۔
ساتویں منصوبے یعنی بیرون ملک امدادی مراکز کے قیام کی سمت میں ہیڈ کوارٹر کابل میں تھا۔ یہاں کے سربراہ مہندر پرتاب تھے۔ بعد میں مولانا سندھی ان سے جا ملے اور دونوں نے مل کر کام کیا۔ اس ہیڈ کوارٹر کی شاخیں مدینہ منورہ‘ برلن‘ استنبول‘ انقرہ اور قسطنطنیہ میں تھیں۔ برلن میں لالہ ہردیال نے نمایاں کام کیا۔ ان کی کوشش سے جرمنی اور ترکی کا پیکٹ ہوا اور جرمنی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آمادہ ہوگیا۔ کابل کے ہیڈ کوارٹر نے فقید المثال کارنامہ انجام دیا۔ امیر حبیب اللہ اور اس کے لڑکے عنایت اللہ کے دوغلے پن (جو بعد میں غداری پر منتج ہوا) کے باوجود تحریک کے آدمیوں کو افغانستان کی سیاست میں اتنا عمل دخل حاصل ہوگیا کہ تحریک کی ناکامی کے بعد قائدین کے دوست اور ہمدرد افسروں نے امیر حبیب اللہ خان کو قتل کروا کر اس کے بیٹے خان امان اللہ کو تخت پر بٹھایا جنہوں نے شروع سے تحریک کی اخلاقی اور مالی مدد کی تھی۔ انہوں نے تخت پر بیٹھتے ہی تحریک کے نظر بند قائدین کو رہا کر کے اپنا مشیر بنا لیا۔ قائدین تحریک ہی کے مشورے سے امان اللہ خان نے انگریزوں سے دو دو ہاتھ کیے اور ۲۳ اگست ۱۹۱۹ء کو افغانستان کو مکمل آزاد کروا لیا۔ مولانا سندھی افغانستان میں چوری چھپے داخل ہوئے تھے تو فوج کے سپہ سالار نادر شاہ نے قندھار میں ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ جب قائدین تحریک کے ایماء پر انگریزوں سے لڑنے کے بارے میں رائے معلوم کرنے کے لیے جرگہ بلایا گیا تو حبیب اللہ خان کے سوا سب لوگوں نے لڑائی کے حق میں رائے دی۔ ان میں امان اللہ خان اور عنایت اللہ خان اور ان کا بھائی نصر اللہ خان پیش پیش تھے۔
آٹھواں منصوبہ یہ تھا کہ برطانیہ اور ترکی کی آویزش میں (وسیع تر مقصد یہ تھا کہ ترکی کے ہندوستان پر حملے کے لیے) بعض ملکوں مثلاً روس‘ جرمنی‘ فرانس اور امریکہ کو ترکی کی حمایت پر آمادہ کیا جائے۔ اس ضمن میں کراچی میں اکابرین تحریک کی ایک مجلس مشاورت ہوئی۔ مولانا محمد علی کا خیال تھا کہ امریکہ ترکی کا ساتھ دے گا کیونکہ وہ خود بھی برطانیہ کا غلام رہ چکا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا خیال تھا کہ امریکہ غیر جانبدار رہے گا لیکن شیخ الہند کا موقف تھا کہ امریکہ برطانیہ کی کھلے بندوں مدد کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا تاہم امریکہ اور فرانس کے انصاف پسند لوگوں نے برطانیہ کے خلاف احتجاج کیا اور تحریک کا مشن کسی حد تک کامیاب رہا۔
روس میں بھی تحریک کا مشن حکومت کی سطح پر ناکام رہا۔ زار نے مشن کے قائدین ڈاکٹر مرزا احمد علی اور ستھرا سنگھ کی گرفتاری کا حکم دیا لیکن تاشقند کے گورنر نے جو تحریک کے کارکن بن گئے تھے انہیں گرفتاری سے بچا لیا۔ اس مشن کا تذکرہ روس کے انقلابیوں نے اپنے ایک پمفلٹ میں بھی کیا تھا اور اسے موثر قرار دیا تھا۔ عوامی سطح پر مشن اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور روس برطانیہ دوستی خطرے میں پڑ گئی جس کے لیے لارڈ کچز خود روس پہنچا۔ البتہ ایک دوسرا مشن جو روس کے راستے جاپان جا رہا تھا زار کے ہتھے چڑھ گیا۔ بد قسمتی سے ستھرا سنگھ جو اس مشن میں شامل تھے اپنے ساتھی عبد القادر سمیت انگریزوں کے حوالے کر دیے گئے۔ انگریزوں نے ستھرا سنگھ کو پھانسی دے دی اور عبد القادر کو لمبی قید کی سزا دی۔
بیرون ملک تحریک کو صرف جرمنی میں کامیابی حاصل ہوئی۔ راجہ مہندر پرتاب نے وہاں تین سال رہ کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ پروفیسر برکت اللہ اور لالہ ہردیال نے بھی ان کی اعانت کی۔ اس سلسلہ میں جرمنی کے کیپٹن ہنٹس نے بڑی مدد کی وہ محاذ کے معائنے کے لیے کابل بھی گیا۔ یہ کوششیں بار آور ہوئیں اور جرمنی ترکی کی مدد کرنے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آمادہ ہوگیا۔ مطمئن ہو کر راجہ مہندر پرتاب کابل چلے گئے جہاں مولانا سندھی بھی پہنچ گئے۔
نویں منصوبے میں حملے کے لیے راستوں کا تعین کرنا تھا۔ ایران‘ برطانیہ کا حلیف اور ترکی کا دشمن تھا۔ اس لیے وہ راستہ ترک کرنا پڑا‘ دوسرا راستہ افغانستان تھا۔ امان اللہ خان اور سول اور فوجی افسروں اور قبائل کے اٹل فیصلے سے ڈر کر حبیب اللہ خان راستہ دینے پر آمادہ ہوگیا۔ لیکن انگریز دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے تجویز پیش کی کہ ترکی فوج بعض مخصوص دروں سے گزرے‘ ہم انگریزوں سے کہہ دیں گے کہ وہاں کے قبائلی باغی ہوگئے ہیں اور ہم مجبور ہیں اس کے علاوہ سرکاری فوج جنگ میں حصہ نہ لے البتہ رعایا رضا کارانہ طور پر حصہ لے سکتی ہے۔ در اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ فریقین میں جس کا پلہ بھاری دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہو جاؤں گا۔
امان اللہ خان اور نصر اللہ خان نے قائدین تحریک کو سمجھایا کہ اسی پر اکتفا کر لیں جب ترکی کی فوج ملک میں داخل ہو جائے گی تو ہم اپنے باپ کو انگریزوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیں گے ورنہ اسے راستہ سے ہٹا دیں گے۔ حملہ کے لیے چار محاذ بنائے گئے۔ ہر محاذ پر ایک انقلابی کو نگران مقرر کیا گیا۔ مولانا محمد صادق کی نگرانی میں قلات اور مکران کے قبائل کا ترک فوج کی قیادت میں کراچی پر حملہ‘ حافظ مولانا تاج محمود سندھی کی نگرانی میں ترک فوج کی سربراہی میں غزنی اور قندھار کے قبائل کا کوئٹہ پر حملہ‘ درہ خیبر کے راستہ پشاور پر مہمند اور مسعود قبائل کا ترک فوج کی قیادت میں حملہ‘ نگران حاجی صاحب ترنگ زئی تھے‘ اوگی ہزارہ کے محاذ پر ترکی کی فوج کا کوہستانی قبائل کو لے کر حملہ‘ نگرانی مولانا محمد اسحاق مانسہروی کی تھی۔
دسویں منصوبے کا مقصد حملے اور بغاوت کی ایک تاریخ مقرر کرنا تھا۔ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۴ء تک نو منصوبوں کو کامیابی سے عملی جامہ پہنایا گیا اور دسویں پر عمل باقی تھا کہ جنگ عظیم چھڑ گئی۔ یہ انقلابیوں کے لیے سنہری موقع تھا فوراً دیوبند میں مجلس مشاورت منعقد ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بیرونی حملہ اور اندرونی بغاوت ۱۹ فروری ۱۹۱۷ء کو ہو مجلس شوریٰ نے اس کی اطلاع تمام شاخوں کو دے دی اور کہا کہ بغاوت کے لیے تیار رہیں لیکن حملے کی تاریخ کے حتمی فیصلے کے لیے دوسری اطلاع کا انتظار کریں۔ شیخ الہند کو ایک وثیقہ لکھ کر دیا گیا جس پر مجلس شوریٰ کے اراکین نے دستخط کیے۔ طے کیا گیا کہ شیخ الہند غازی انور پاشا سے بالمشافہ مل کر مجوزہ تاریخ کی منظوری لیں اور تحریک اور حکومت کے مابین نیز حکومت ترکی اور حکومت افغانستان کے درمیان تحریری معاہدہ کرائیں ۔ اس دوسرے معاہدہ کے سلسلہ میں انہیں انور پاشا کی تحریر لے کر افغانستان جانا تھا اور اس پر حبیب اللہ خان سے دستخط لے کر واپس انور پاشا کو پہنچانا تھا۔
شیخ الہند نے اپنی جائیداد شرعی قانون وراثت کے مطابق تقسیم کردی اور حج کا ارادہ ظاہر کر کے روانہ ہوگئے۔ حکومت نے انہیں دہلی میں گرفتار کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کے معتقدین کا ہجوم دیکھ کر بمبئی میں گرفتار کرنے کی ٹھانی۔ ڈاکٹر انصاری نے خفیہ پولیس میں اپنے آدمیوں کی مدد سے اس تار کو ہوم سیکرٹری کے دفتر میں رکوا دیا جو اس مقصد سے گورنر جنرل کی طرف سے بمبئی کے گورنر کو بھیجا جا رہا تھا۔ یہ تار اس وقت ملا جب آپ جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ چنانچہ عدن کے گورنر کو روانہ کر دیا گیا لیکن وہاں بھی انقلابیوں نے بروقت پہنچنے نہ دیا اور آپ بخیر و عافیت مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اس وقت حجاز ترکی کے زیر حکومت تھا۔ وہاں کے گورنر غالب پاشا جو انور پاشا کی جنگی کمیٹی کے سیکرٹری بھی تھے‘ انقلابی تحریک کے ہمنوا تھے۔ شیخ الہند نے ان سے دو تحریریں لیں۔ ایک میں جہاد کی ترغیب تھی اسے چھپوا کر ہندوستان اور افغانستان کے نام تھی کہ شیخ الہند جو کچھ بھی کہیں اسے ہماری تائید حاصل ہے۔ انگریزوں نے اس پہلی تحریک کو غالب نامہ کہا اور اسی کی بنا پر بعد میں غالب پاشا کو گرفتار کر کے جنگی قیدی رکھا۔ انہوں نے بھی اپنی اس تحریر کا اقرار کیا‘ دوسری کا نام تک نہ لیا۔
شیخ الہند نے "غالب نامہ" مولانا محمد میاں کے حوالے کیا کہ اسے ہندوستان اور افغانستان لے جائیں۔ وہ ہندوستان پہنچے تو سی آئی ڈی پیچھے لگ گئی۔ چنانچہ افغانستان چلے گئے اور اس کی اشاعت کی۔ اسی اثنا میں ریشمی رومال کے پکڑے جانے کے بعد افغانستان پہنچی۔ البتہ اس سے افسروں اور قبائلی سرداروں میں نیا عزم پیدا ہوا اور امان اللہ خان انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔
شیخ الہند اور انور پاشا کی ملاقات مدینہ منورہ میں ہوئی ۔ جمال پاشا ان کے ساتھ تھے۔ انور پاشا نے پہلے ان سے تحریر کردہ دونوں معاہدے لے لیے اور واپس چلے گئے۔ ایک ماہ بعد یہ معاہدے شیخ الہند کو مدینہ منورہ کے گورنر نے بلا کر دیے۔ ان پر انور پاشا کے دستخط ثبت تھے اور حملے اور بغاوت کی منظوری بھی تھی۔ دونوں معاہدوں کا مجموعی نام "انور نامہ" رکھا گیا۔ شیخ الہند نے تحریر اور حکومت ترکی کے معاہدے کو اپنے پاس رکھ لیا اور افغانستان ترکی معاہدہ مولانا ہادی حسن کو دے کر انہیں بھیج دیاکہ اسے افغانستان پہنچا دیا جائے۔ اس دستاویز کو بھجوانے میں شیخ الہند نے غیر معمولی حسن تدبیر سے کام لیا۔ خاص طور پر سے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا۔ اس کے تختوں کے درمیان اس طرح چھپوایا کہ نظر نہ آتا تھا۔ ساتھ ہی بمبئی کے ایک رکن کو پیغام بھجوایا کہ وہ عرشہ جہاز پر ہی مولانا ہادی حسن سے صندوق لے لیں اور اسے فلاں پتے پر پارسل کر دیں۔ جوں ہی جہاز بمبئی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ وہ رکن عرشہ جہاز پر گئے اور اسے قلیوں سے اٹھوا کر باہر لے گئے۔ اسی وقت اسے مظفر نگر میں حاجی محمد نبی کے پتے پر پارسل کروا دیا۔ سی آئی ڈی نے مولانا ہادی حسن کی تلاشی لی اور انہیں مشتبہ قرار دے کر نینی تال بھجوا دیا جہاں انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔
حاجی محمد نبی کو شیخ الہند نے ساری بات کہلوا بھیجی تھی۔ انہوں نے معاہدے کو اپنے پاس رکھا۔ کچھ عرصہ بعد مولانا ہادی حسن رہا ہو کر آئے۔ انہوں نے حلیہ بدل کر اپنا نام ظفر احمد رکھا اور معاہدے کو افغانستان پہنچا دیا ۔حبیب اللہ خان نے اپنے دونوں بیٹوں امان اللہ خان اور نصر اللہ خان اور سول فوجی افسروں اور قبائلی سرداروں کو آتش زیرپا دیکھا تو طوعاً و کرھاً اس کی منظوری دے دی۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور نصرت اللہ خان نے ایک ماہر کاریگر سے معاہدے کی ساری عبارت جو عربی زبان میں تھی‘ ایک ریشمی رومال پر کڑھوائی اس میں حبیب اللہ خان اور اس کے تینوں بیٹوں کے دستخط بھی آگئے۔ رومال کا رنگ زرد تھا۔ اس کی لمبائی چوڑائی ایک مربع گز تھی۔ اس پر زرد رنگ سے چاروں کے دستخط دوبارہ کروا لیے گئے۔ اس کے بعد رومال کو پشاور بھجوایا گیا۔ یہ فرض شیخ عبد الحق نے انجام دیا جو بنارس کے نو مسلم گریجویٹ تھے اور افغانستان ہندوستان کے درمیان کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اسی تجارت کی آڑ میں پیغام رسانی کرتے تھے۔ انہوں نے اسی قسم کے پانچ رومال لیے اور ریشمی رومال کو ان میں ملا دیا۔ پروگرام یہ تھا کہ رومال حیدر آباد میں شیخ عبد الرحیم کو پہنچایا جائے گا جو اسے لے کر حج کو جائیں گے اور شیخ الہند کے حوالے کریں گے۔ موصوف اسے انور پاشا کو لے جا کر دیں گے اور پروگرام کے مطابق ترکی‘ افغانستان کے راستے ۱۹ فروری ۱۹۱۸ء کو ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔
شیخ عبد الحق نے یہ امانت پشاور میں حق نواز خان کو رات نو بجے پہنچائی انہوں نے صبح چار بجے اسے ایک خاص آدمی کے ہاتھ بہاول پور کے مقام دین پور میں سجادہ نشین خواجہ غلام محمد کو بھجوا دیا۔ نماز صبح سے پہلے فوج نے حق نواز کے گھر پر چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کی رہائی ایک ماہ بعد ہوئی۔ خواجہ غلام محمد کو رومال اگلے دن دس بجے صبح ملا۔ انہوں نے اسی وقت اسے ایک آدمی کے ہاتھ حیدر آباد چلتا کیا۔ ان کے گھر پر بھی فوج نے شام کے چار بجے چھاپہ مارا اور انہیں گرفتار کر لیا ۔چار ماہ تک قید رہے۔ ریشمی رومال دوسرے دن دوپہر کو حیدر آباد میں شیخ عبد الرحیم کو ملا اور عشاء کے وقت جب وہ اسے گدڑی میں سی رہے تھے‘ فوج کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس دستاویز کے ہاتھ آجانے سے انگریزوں کو مجاہدین اور حکومت ترکی کے تفصیلی عزائم کا ثبوت مل گیا۔ انہوں نے داخلی طور پر یہ فوری قدم اٹھایا کہ ہر اس مقام پر فوج بھیج دی جہاں بغاوت کا خطرہ تھا اور شمال مغربی سرحد پر فوج دگنی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں انقلابیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی۔ جس شخص پر ذرا سا شبہ گزرا اسے گرفتار کر لیا ‘ گرفتار شدگان پر طرح طرح کی سختیاں کیں۔ دو چار کے سوا سب ہی ثابت قدم رہے تاہم تحریک دفن ہوگئی۔
خاص طور پر سب سے پہلے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ترکی کی ہر سرحد پر محاذ کھول دیے۔ ایران میں فوج داخل کر کے ترکی اور افغانستان کے درمیان حد بندی کر دی۔ سب سے بڑا انتقام یہ لیا کہ شریف مکہ کو آلہ کار بنا کر اس سے ترکی کے خلاف بغاوت کرا دی۔ اس کے علاوہ عرب اور ہندوستان کے زر خرید ایجنٹوں سے ترکوں کے خلاف فتوے دلوائے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں کو موقع مل گیا تھا کہ افغانستان کو دبائیں لیکن تحریک کے جو کارکن وہاں گرفتاری سے بچ رہے تھے انہوں نے قبائلیوں کی بڑی رہنمائی کی۔ حاجی ترنگ زئی نے قبائلیوں کو جمع کر کے تین سال تک انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ قلات اور لسبیلہ کے قبائل نے دو سال تک مقابلہ کیا۔ امان اللہ خان نے کوہاٹ تک قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن انگریزوں سے صلح ہوگئی اور افغانستان کی مکمل آزادی اور خود مختاری تسلیم کر لی گئی۔ شیخ الہند کو مکہ معظمہ میں گرفتار کرلیا گیا۔ ان پر مصر کی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور پھر جنگی قیدی بنا کر مالٹا بھیج دیا گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو ہندوستان آئے کچھ عرصہ خلافت تحریک میں کام کیا اور رحلت فرمائی۔
اس ضمن میں ریشمی رومال پکڑا کیسے گیا؟ کچھ مصدقہ اور کچھ غیر تصدیق شدہ باتیں ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا خیال تھا کہ پشاور کے نواز خان نے مخبری کی لیکن مولانا حسین احمد مدنی کو اس سے اختلاف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حبیب اللہ خان اور اس کا لڑکا عنایت اللہ خان مجاہدوں کے ہر منصوبے کی انگریزوں کو باقاعدہ رپورٹ پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں کی غدار فطرت کے سبب یہ بات خارج از امکان نہیں ہے۔ غداری کے سلسلے میں تحریک کے اکثر ارکان متفق ہیں کہ انگریزوں کے جاسوس مجاہدین کے روپ میں تحریک میں گھس گئے تھے اور کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے بھی راز اگل دیے۔
من از بیگانگاں ہرگز نہ نالم
کہ بامن ہرچہ کرد آں آشنا کرد
غیر ملکی قرضوں کا جال اور پاکستان کی آزادی
لیفٹیننٹ جنرل (ر) حمید گل
عالمی سود خوروں نے قرضے کا قطرہ ایک بار پھر ہمارے خشک منہ میں ٹپکا دیا۔ ۱۹۷ ملین ڈالر کی حقیر رقم ہماری آزادی‘ معیشت اور مستقبل کی قیمت ٹھہرائی گئی ہے۔ ایک بار پھر ہماری تمام اقتصادی ‘ معاشی اور سیاسی پالیسی پر آئی ایم ایف اور دوسرے عالمی اداروں کے ذریعے امریکہ کو تسلط کا حق حاصل ہوگیا ہے۔ ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۹ء کے بعد آزادی کے حصول کے جو امکانات روشن ہوگئے تھے ختم ہو کر رہ گئے ہیں چنانچہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جس طرح بیرونی قوتوں کے حکم پر قانون و آئین کے منافی جیل سے نکال کر سعودی عرب پہنچایا گیا اس سے ثابت ہوگیاکہ پاکستان کی حکومت اور عوام اپنی مرضی اور اپنے آئین کے بجائے امریکہ کی مرضی اور حکم کے پابند ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم قرضوں کے جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔
غیر ملکی قرضوں کا مسئلہ بہت پرانا ہے ایوب خان کے زمانہ میں بھی ہم مقروض تھے لیکن تب ہر پاکستانی صرف ساٹھ روپے کا مقروض تھا۔ آج ہمارا ہر شہری یہاں تک کہ نوزائیدہ بچہ بھی ۲۵۰۰۰ روپے کا مقروض ہے۔ موجودہ ۳۷ بلین ڈالر (۲۳ کھرب پاکستانی روپے) کا غیر ملکی قرضہ اگر عوام کو ادا کرنا پڑے تو ہر خاندان پر دو لاکھ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا جس میں صدر مملکت سے لے کر ایک غریب مزدور اور ہاری سب ہی شامل ہوں گے۔ قیام پاکستان کے وقت ایک ڈالر ہمارے ایک روپے کے برابر تھا جو ایوب دور میں بڑھ کر نو روپے کا ہوگیا اور آج ساٹھ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں اس سال پانچ ارب ڈالر (تین سو ارب روپے) ادا کرنے ہوں گے جب کہ ہماری مجموعی برآمدات کا حجم بے پناہ کوششوں کے باوجود آٹھ ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف پوری کوشش کے باوجود ٹیکسوں کی مد میں ایک سو ارب روپے سے زیادہ اضافے کی امید نہیں۔ ماضی کے تجربات ‘ معروضی حالات اور مستقبل کے امکانات کو نگاہ میں رکھیں تو اس بات کا دور دور تک امکان نظر نہیں آتا کہ پاکستان یہ قرضے ادا کر سکتا ہے ۔ ہمارے موجودہ حکمران اب تک دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ قرضے ادا کریں گے لیکن عملی صورت یہ ہے کہ یہ بھی پرانے قرضے ادا کرنے کے بجائے نئے قرضے لے رہے ہیں۔ ہم اپنے بل بوتے پر اغیار کا بچھایا ہوا غلامی کا یہ جال توڑ سکتے ہیں لیکن اس کام کے لیے جس درویش صفت اور بے لوث قیادت کی ضرورت ہے ہم اس سے محروم ہیں۔ ہمیں وہ لیڈر شپ میسر نہیں جس کی آواز پر ساری قوم لبیک کہے اور شعب ابی طالب میں محصور ہونے کا آپشن قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ لہذا موجودہ صورت حال کے تناظر میں دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں۔
پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف اور امریکہ کے سامنے مکمل سرنڈر کی راہ اپنا لیں۔ ایٹمی صلاحیت ختم کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ اپنی خارجہ پالیسی امریکہ کے تابع کر لیں‘ کشمیر سے دستبردار ہو جائیں اور جہاد کشمیر ختم کرنے میں امریکہ اور بھارت کا ہاتھ بٹائیں۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے ہماری اقتصادی حالت بہتر ہو سکے گی یا قرضے معاف کر دیے جائیں گے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں اور یہ راستہ اختیار کرنے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے‘ نظریے اور آزادی سے محروم ہونا قبول کرلیں۔
دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم قرضے ادا کرنے سے انکار کر دیں جب تک ادا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس انکار کی معقول وجوہ ہیں:
۱۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہ Odious Loans ظالمانہ اور غلیظ قرضے لیتے وقت ہماری حکومتوں نے قوم سے نہیں پوچھا۔ چاہے وہ مارشل لا کی غیر جمہوری حکومتیں ہوں یا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی جمہوری حکومتیں‘ عوام سے کسی نے پوچھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ لہذا ان جبری قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ غریب عوام پر ڈالنا آئین‘ قانون اور اخلاق کے کسی قرینے سے جائز نہیں۔
۲۔ ان کی دیدہ دانستہ غلط پلاننگ mis management قرضے دینے والے ملکوں اور اداروں نے کی۔ اس دانستہ بد انتظامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے بھاری قرضوں سے ملک اور قوم کو فائدہ نہ پہنچا سوائے ایوب دور کے جب تربیلا اور منگلا وغیرہ تعمیر ہوئے۔ گزشتہ بارہ سال کے دوران ۲۳ ارب ڈالر کے قرضے لیے گئے۔ ان سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا۔ سوائے موٹر وے کے جو ان قرضوں میں شامل نہیں۔ کوئی چھوٹا بنک بھی غیر معینہ یا ناقص منصوبے کے لیے قرض نہیں دیتا تو آئی ایم ایف اور عالمی بینک نے قرضے کیوں دیے۔ در اصل یہ رقم قرض دینے والوں کے ایما پر لوٹ لی گئی اور لوٹ مار کا یہ مال ان ہی بینکوں میں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ اب لوٹ کے مال کے پیچھے لوٹنے والے بھی وہاں جا پہنچے ہیں لہذا قانون‘ اخلاق اور عقل و منطق کے کسی اصول کے تحت پاکستان کے عوام پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بد انتظامی کی ذمہ داری سے قرض دینے والے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔
قرض دینے والے بنک اور ملک دیکھ رہے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قرضے قوم کے بجائے چند افراد کے مفادات پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ان عالمی اداروں کو معلوم تھا کہ ان قرضوں کا ثمر عوام کو نہیں ملے گا لیکن چونکہ قرض لینے والے ان کے سیاسی اور معاشی ایجنڈے پر عمل پیرا تھے اس لیے وہ کسی اصول اور ضابطے کے بغیر ہماری رقوم جاری کرتے رہے‘ مقروض ملکوں میں ان قرضوں کی مدد سے من پسند حکومتیں بھی لاتے رہے اور ان قرضوں کے عوض ایسی اقتصادی پالیسیاں بناتے اور چلاتے رہے جن سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ عوام کے نام پر لیا قرضہ چند افراد کے بنک اکاؤنٹس میں پہنچ رہا ہے۔ کون بتا سکتا ہے کہ گزشتہ بارہ برس میں لیا گیا ۲۳ ارب ڈالر (ساڑھے تیرہ کھرب روپے) کا قرضہ کہاں گیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ قرض کہاں خرچ ہوا؟ اس کے علاوہ نواز شریف کے دور میں عوام کے منجمد گیارہ ارب ڈالر (چھ سو ساٹھ ارب روپے) کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ موجودہ حکومت نے احتساب کا وعدہ کیا تھا لیکن اس نے سابق وزیر اعظم کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی‘ ایسا لگتا ہے کہ اسے بھی احتساب کے پورے سلسلے کو فراموش کرنے میں ہی عافیت نظر آئی ہے۔
۳۔ قوم کو ان ظالمانہ قرضوں میں جکڑ کر نہ صرف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے قرضے مع سود واپس کرو بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری روٹی‘ روزگار اور روشنی کا فیصلہ بھی ہم کریں گے۔ چنانچہ آئی ایم ایف کے کہنے پر گیس‘ بجلی اور آٹے پر غریبوں کے لیے رعایت Subsidy بھی ختم کر دو‘ کرنسی کی قیمت کم کرو‘ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے تمام ذرائع اور وسائل کثیر ملکی (Multi National) کمپنیوں کے حوالے کر دو۔ ایٹمی صلاحیت ختم کرنے کے لیے سی ٹی بی ٹی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے میں پسپائی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ان سارے معاملات کے لیے قرضوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
ہمارے اقتصادی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت سنبھل رہی ہے۔ یہ ایک سفید جھوٹ ہے‘ عوام معاشی بدحالی اور بیروزگاری کے ہاتھوں خودکشی کر رہے ہیں۔ مہنگائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ بجلی‘ پٹرول اور گیس کی قیمتیں بار بار بڑھائی جا رہی ہیں‘ یہ کیسی معاشی ترقی ہے؟ ہم پانچ ارب ڈالر سالانہ ادا کر کے کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ سلسلہ جاری رہا تو آئندہ چند برسوں کے اندر قرضے کی قسطیں ہمارے مجموعی بجٹ سے بھی بڑھ جائیں گی۔ معیشت کا احیا تو کجا الٹا ہماری آزادی اور بقا خطرے میں ہے۔ ہمارے اقتصادی دانشوروں کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے قرضے دینے سے انکار کیا تو ہمیں ڈیفالٹ قرار دے کر دنیا میں تنہا کر دیا جائے گا‘ برآمدات نہیں ہوں گی‘ ایل سی نہیں کھلے گی‘ یہ دانش بھی مغرب سے ہمارے ہاں آئی ہے۔ یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ ہماری برآمدات ختم ہو جائیں گی۔ برآمدات کا سلسلہ چین‘ افغانستان‘ ایران اور دیگر اسلامی ممالک سے جاری رہ سکتا ہے‘ جن پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اس طرح ایک نیا تجارتی بلاک وجود میں آسکتا ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ خرچ تیل پر ہوتا ہے جس کے بدلے ہم تیل پیدا کرنے والے ممالک کو چاول‘ گندم اور کپاس برآمد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ کرنے والا پاکستان پہلا ملک نہیں ہوگا۔ لاطینی امریکہ کے سولہ ملک ڈیفالٹ کر چکے ہیں جس کے بعد ان کی معیشت میں بہتری کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں تک تنہائی کا معاملہ ہے تو چین اور روس نے سیاسی طور پر تنہا ہو کر ہی ترقی کی۔ دراصل یہ اقتصادی دانشور ایک سازش کے تحت ہمیں سمجھانے پاکستان آتے ہیں اور ہر بار ہمیں ایٹمی پروگرام‘ کشمیر اور دفاعی بجٹ میں کمی کرنے کی تلقین کا سلسلہ دوبارہ چالو کرا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی اور سیاسی تنہائی پاکستان کے حق میں خوش بختی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ میرے یقین کے پیچھے ٹھوس دلائل ہیں:
- سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہمیں حاصل ہوگی جب ہم تمام جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر صرف اس کا دامن تھامیں گے تو وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہم پیغمبر آخر الزمانؐ کے نام لیوا ہو کر تنہائی سے کیوں ڈریں جنہوں نے شعب ابی طالب میں رہ کر اقتصادی مقاطعے کا سامنا کیا اور جنگ احزاب میں دشمنان اسلام کی متحدہ قوت کو پسپا کیا۔
- دنیا میں وہ تمام ممالک جنہیں سیاسی طور پر تنہا کیا گیا اور جن کے خلاف استعماری ملکوں نے اتحاد کیا وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوگئے۔ ان کے عوام کے خفیہ جوہر بروئے کار آگئے۔ جاپان‘ روس‘ چین اور ان گنت دوسرے ممالک کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ چین پاکستان کے بعد وجود میں آیا‘ وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ ایران‘ عراق‘ سوڈان اور لیبیا کو تنہا کیا گیا لیکن وہ سب زندہ رہے۔ کیوبا ایک چھوٹا سا بے وسیلہ ملک ہے۔ اس کو تنہا کیا گیا لیکن فیڈرل کاسترو کا بال تک بیکا نہ ہو سکا۔ پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے ‘ اسے تنہا رکھنا اول تو ناممکن ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان ملت اسلامیہ کا قائد بن جائے گا پھر عین ممکن ہے تیل کی دولت سے مالا مال اسلامی ممالک پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ اگر مغرب کی استعماری افواج کو اربوں ڈالر کی تنخواہ دے سکتے ہیں تو پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے میں مدد کیوں نہیں دے سکتے۔
- تنہائی کی مصیبت میں ایک رحمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر پاک سرزمین کو اسلامی نظام کی برکات سے فیض پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسلام کو عروج اور ترقی شعب ابی طالب میں فاقہ کشی اور غزوہ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد ملی تھی۔ اس لیے ہمارے لیے تنہائی کوئی تباہی نہیں لائے گی بلکہ ہم یکسو ہو کر نئے نظام کی بنیاد رکھیں گے۔
- پاکستان میں قیادت کا بحران اس وجہ سے پیدا ہوا کہ استعماری طاقتوں نے ہماری آزادی پر کنٹرول قائم کیا اور اپنے ایجنٹ اور کرائے کے لیڈر پاکستان پر مسلط رکھے اور عوام کو کوئی مخلص قائد نہ مل سکا۔ پاکستان تنہا ہوگا تو عوامی مزاحمت کی راہنمائی کرنے والی حقیقی قیادت ابھرے گی جو اپنے مفادات پر عوام کو قربان کرنے اور ان کا خون چوسنے کے بجائے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرے گی۔ ایک حقیقی لیڈر شپ پیدا ہوگی جو پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے کی اہل ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے تنہائی اختیار کی تو اسے ماؤزے تنگ اور چو این لائی جیسے بے نفس اور بے لوث لیڈر ملے۔ یہ سامنے کی بات ہے کہ جن ممالک کو تنہا کیا گیا ان کے لیڈروں کا دور قیادت طویل تر ہے۔ چین کے موزے تنگ‘ شمالی کوریا کے کم ال سنگ‘ کیوبا کے فیڈل کاسترو‘ لیبیا کے معمر قذافی اس کی مثال ہیں۔ ایران کے خمینی زندگی کے آخری سانسوں تک عوام کے دلوں میں زندہ رہے۔ اسی طرح صدام امریکہ اور مغرب کی تمام تر مخالفت کے باوجود تیس برس سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس جو حکمران مغرب کے سامنے جھک گئے ہیں ان کا دورانیہ چند سال کا ہوتا ہے چونکہ وہ اپنے آقاؤں سے مخلص ہوتے ہیں اور قوم کے وفادار نہیں ہوتے اس لیے قوم انہیں جلد ہی نظروں سے گرا دیتی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے عزت اور آبرو کا راستہ کھلا ہے۔ ہمیں پوری قوت سے اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم غیر ملکی قرضے ادا نہیں کر سکتے اور نہ قرضوں کی خاطر اپنے ملک کی آزادی کو امریکہ کے پاس گروی رکھ سکتے ہیں۔ ہماری قوم اس پر متفق ہے ۔ میں اس مقصد کے لیے تحریک شروع کر چکا ہوں ۔ اب تک سرگودھا اور سیالکوٹ کی بار کونسلوں سے خطاب کر چکا ہوں جہاں وکلا برادری نے مکمل اتفاق رائے سے قراردادیں منظور کی ہیں جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ استعماری قرضے ادا کرنے سے انکار کر دے۔ میری درخواست ہے کہ قومی پریس اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے اور عوامی رائے کو منظم شکل میں ابھارے ۔میں ان شاء اللہ گھر گھر جا کر لوگوں سے کہوں گا کہ اگر ہم سسک سسک کر اور ذلت سے جینا نہیں چاہتے ‘ اگر ہم نہیں چاہتے کہ مٹھی بھر غیر ملکی ایجنٹ قوم کا مال لوٹ کر غیر ملکی بینکوں میں لے جائیں اور ہمارے قومی مجرموں کو امریکہ ہمارے آئین و قانون کے ہاتھوں چھڑا کر لے جائے تو ہمیں مزاحمت کرنا ہوگی۔ ہمیں قرضوں کی سازش کا شکار بننے سے صاف انکار کرنا ہوگا۔ ہم اپنے ایمان‘ نظریے اور آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں عزت سے جینا ہے تو عزت سے مرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سرنڈر کی پالیسی سے موت نہیں ٹلتی۔ اس لیے ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم ذلت سے جینا اور مرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے حکمرانوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں ‘ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں یا اپنی مظلوم مگر غیرت مند قوم کے ساتھ‘ درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔
کشمیر کی آزادی کا واحد راستہ - جہاد
الشیخ عمر بکری محمد
اسلام کو کشمیر میں سن ۵۰۰ ہجری (۱۲۰۰ عیسوی) میں نافذ کیا گیا۔ برطانیہ کے مداخلت کرنے اور سکھوں کے کشمیر پر (۱۸۱۹) میں قبضہ کرلینے سے پہلے تک اسلام وہاں غالب رہا۔ ۱۸۴۶ء سے یہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہے جب گلاب سنگھ نے اسے برطانیہ کو صرف ساڑھے سات ملین روپے میں بیچ دیا۔ یہ برطانیہ ہی تھا جو انڈین برصغیر کو تین واضح خطوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ دار تھا جبکہ انہوں نے عرب جزیرہ نما کو کئی مزید حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اسلام کی غیر موجودگی سے قتل و غارت اور تشدد آئے ہیں کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں ایسا کوئی ہمدردی اور رحم کا عنصر نہیں ہے۔ یہ برطانیہ تھا جس کی راہنمائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کی‘ جس نے ہندوؤں کے ساتھ نرمی برتتے ہوئے کشمیر کو ان کی عمل داری میں دینا یقینی بنا دیا اور نتیجے کے طور پر کشمیر پر کفار کا قبضہ ہوگیا۔
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:
"اے ایمان والو ! ان مشرکین سے لڑو جو تمہیں گھیرے میں لے لیں اور ان کو تمہاری اندر کی سختی دیکھ لینے دو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔" (۱۲۳ : ۹emq )
اللہ حکم دیتا ہے کہ جہاد ہی ظالم ہندوؤں کے خلاف واحد حل ہے۔ مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مشرکین سے جنگ کریں اور وہاں پر پھر سے اسلامی حکومت لے آئیں۔ پاکستان‘ بنگلہ دیش‘ افغانستان کی مسلم افواج افواج کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جنگ کریں۔ اسلام میں ایسی کوئی گفت و شنید کے ساتھ تصفیہ کی صورت نہیں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ مشرکین نہیں چاہیں گے کہ اسلام کسی صورت پھلے پھولے۔ یہ مشرکین ہی ہیں جنہوں نے پہلے ۱۹۲۴ء میں اسلامی خلافت کو تباہ کر کے مسئلہ پیدا کیا۔
مسلمانوں کو صرف روزے اور نماز ہی میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
"اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اللہ کے سوا کسی دوسرے آقا کی پیروی نہ کرو‘ تم تھوڑا یاد رکھتے ہو۔" (۳:۴ tmq)
قوم پرستی نے مسلمانوں کو ان کی جمہوریت کی طرف مطالبے کا جواز دیا ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کب مسلمان کفار کے غلبے سے نجات حاصل کرنے کے لیے الگ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کشمیر میں ظلم کے وجود کی وجہ اسلامی نظام کی عملداری نہ ہونا ہے۔
"وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔" (۴۵:۵ tmq)
مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جو قتل و غارت کشمیر‘ فلسطین‘ افغانستان‘ بوسنیا اور چیچنیا میں دیکھتے ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ صرف وہاں کے مسائل نہیں ہیں بلکہ مسلم دنیا سے اسلام کے عملی طور پر غائب ہونے کا بلاواسطہ نتیجہ ہیں۔ اس مسئلہ کی طرف توجہ دی جانی ضروری ہے کیونکہ اس مسئلہ کو حل کیے بغیر ہم مسئلہ کشمیر کا مستقل حل ڈھونڈنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ مسلمانو ! یاد رکھو صرف ۳۱۳ مسلمان غزوہ بدر میں ۱۰۰۰ کی تعداد میں دشمن فوج سے لڑے تھے اور کامیاب ہوئے تھے کیونکہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ فتح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اس عقیدے کی بنیاد پر تمام کفار کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے کہ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کشمیر کے لیے وہی حل ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ باقی تمام کو آزما لیا گیا ہے۔ پچاس سالوں تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ تمام ناکام ہو چکے ہیں۔
"اے جو ایمان لائے ہو ! کیا میں تمہیں ایک ایسا راستہ نہ دکھاؤں جو تمہیں المناک انجام سے بچائے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کے راستے پر اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ جدوجہد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو۔" (۱۱‘۱۰ :۶۱ tmq)
اے مسلمانو ! کشمیر یا بوسنیا یا کسی بھی اسلامی ملک میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو مت فراموش کرنا‘ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا‘ مساجد میں خطبات کے دوران ظلم و جبر کی نشاندہی کرو اور اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر جہاد کے لیے تیار کریں اور ان مسائل کے درست حل (نظام خلافت) کے لیے اسلام کا مطالعہ کریں۔
اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت اور دائرہ کار
مولانا عصمت اللہ
عصر حاضر میں ہر طرف انسانی حقوق (Human Rights) کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یورپی اقوام اس معاملہ میں زیادہ ہی فکر مندی ظاہر کر رہی ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لگتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں زیادہ فکر‘ غم‘ پریشانی انہیں کو لاحق ہے۔ اگرچہ دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ان لوگوں نے کچھ تنظیمیں بھی قائم کر رکھی ہیں۔ ان کی مختلف شاخیں مختلف ممالک میں کام کر رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں اقوام متحدہ بھی اپنی فکرمندی ظاہر کرتا رہتا ہے اور اقوام متحدہ نے اپنے زیر اہتمام کئی شعبے ترتیب دے رکھے ہیں اور ہر سال کچھ دن منانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ کہیں خواتین کے حقوق کا عالمی دن منانے کی صدا بلند کی جاتی ہے‘ کہیں مزدوروں ‘یتییموں‘ بچوں‘ معذوروں کے عالمی دن منانے کا شور مچایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ گویا انسانی حقوق‘ انسانیت کا احترام‘ خواتین کی فلاح و بہبود اور آدمیت کے مقام و مرتبہ کا تصور اور خیال ایک نئی ایجاد ہے۔
یورپی اقوام کے اس طرز عمل سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ اور این جی اوز اقوام عالم کو یہ باور کرانے کی کوشش اور فکر میں مبتلا ہیں کہ انسانیت کی جو عظمت‘ مقام کی بلندی اور حقوق کی ادائیگی کی فکر ان کے اندر ہے‘ وہ کسی اور قوم کے اندر نہیں۔ وہ یوں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات کے پاس تو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا دین و مذہب‘ تعلیمات اسلامیہ‘ تہذیب و تمدن‘ اسلامی معاشرہ اور قرآن و سنت انسانیت کے حقوق اور عظمت سے غافل و بے خبر ہیں۔ ان کے پاس تو اس سلسلے میں کوئی آئینی‘ دستوری‘ تعلیمی‘ تہذیبی‘ فکری‘ نظری‘ علمی و عملی سرمایہ نہیں ہے اور آدمیت کے احترام حقوق کا تصور نیا پیدا ہوا ہے۔
آئیے مختصراً اسلامی تہذیب کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ اسلام کی تعلیمات انسانی حقوق اور عظمت کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں اور اسلام انسانی حقوق کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے۔ اس سے قبل کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے پر تبصرہ کریں‘ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حقائق دوسرے مذاہب اور تہذیبوں مثلاً ہندو مت‘ بدھ مت‘ یہودیت‘ نصرانیت کے بھی پیش کر دیے جائیں تاکہ مسابقت کے اس دور میں اسلام میں انسانی حقوق کے معاملہ کو مقابلہ کی صورت میں سمجھنا آسان ہو سکے۔ اس طرح اسلام کی عظمت و وقار دلوں میں خوب راسخ ہو سکے گی اور تقابلی مطالعہ سے اچھائی‘ برائی‘ اعلیٰ و ادنیٰ‘ بہتر‘ بدتر‘ صدق و کذب اور حق و باطل باسانی سمجھا جا سکے۔
چنانچہ جب ہم دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان مذاہب اور تہذیبوں میں انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل قائم نہیں کی گئی۔ بدھ مت کی تعلیمات میں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔
اسی طرح ہندو قانون میں ایک جانور اور ایک انسان کا قتل برابر کا درجہ رکھتا ہے اور ایک جانور بھی اپنی کسی نفع رسانی کے باعث انسان کی ماں کا درجہ پا سکتا ہے ۔
یہودیت‘ نصرانیت میں قرابت داروں کو چھوڑ کر صرف ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن دوسرے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا۔
دنیا کے ایک بڑے جمہوری نظام کے دعوے دار ملک ہندوستان میں حال ہی میں پیش آنے والے ان واقعات سے ہندو نظام میں انسانی حقوق کی پاسداری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
روزنامہ جنگ میں ہندوستانی انگریزی ہفت روزہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آزادی کے ۵۳ سال بعد بھی کسی نچلی ذات میں پیدا ہونا ہندوستان میں ایک عذاب ‘ ایک لعنت سے کم نہیں۔ اس کا تازہ ترین ثبوت اس وقت ملا جب ایک کانگریسی رکن پارلیمنٹ ویلدروی نے اپنے بیٹے کی شادی کی رسم اپنے علاقے کے مندر میں ادا کی۔ رسم کے بعد مندر کے پرومہت نے حکم دیا کہ ساری عبادت گاہ کو نجاست سے پاک کیا جائے۔ اس کے لیے ایک عظیم عمل کیا گیا۔ مندر نجس کس طرح ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ رکن پارلیمنٹ کی بیوی ایک عیسائی عورت ہے اور وہ بھی اپنے بیٹے کی شادی کی رسم میں شرکت کے لیے مندر میں آئی تھی۔ حالانکہ مسٹر روی ایک زمانے میں صوبائی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں۔
ایک اور مثال سنئے ‘ گزشتہ اگست میں ایک عدالتی افسر بھرھتری پرشاد نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ الٰہ آباد ہائی کورٹ نے یو پی حکومت کی طرف سے جبری طور پر ریٹائر کرنے کے خلاف اس کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسے جبری طور پر اس لیے ریٹائر کیا گیا تھا کہ اس نے حکومت کا ایک حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حکم کیا تھا؟ جب مذکورہ افسر کا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں تبادلہ ہوا تو ان کا جو جانشین جج مقرر ہوا جس کا نام اے کے سری وستوا تھا۔ اس نے عدالت میں بیٹھنا شروع کرنے سے پہلے گنگا جل منگوایا۔ پوری عدالت کو دہلوایا اس لیے کہ میرا پیش رو جو یہاں بیٹھتا رہا ہے وہ ایک نچلی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ دیکھئے آج بھی بھارت میں لوگ ذات پات کی تقسیم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔
اس وقت امریکہ جو انسانی حقوق کا بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے اس کا اپنا یہ حال ہے کہ اس نے جاپان کے دو بڑے شہروں ہیرو شیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم گرائے جس میں لاکھوں جانیں آن واحد میں لقمہ اجل بن گئیں۔ ہزاروں مکان زمیں بوس ہوگئے اور دونوں شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اسی طرح جب مشرقی تیمور کے عیسائیوں کامسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی حمایت میں امریکہ‘ اقوام متحدہ اور پورا یورپ کھڑا ہو جاتا ہے اور انسانی حقوق کا اس قدر شور و غل بپا کیا جاتا ہے کہ اس کو آزادی دلا کر ہی چین لیتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں یہ کشمیر ہے۔ ۵۳ برس سے آزادی کا مطالبہ کر رہا ہے‘ اس کی قراردادیں امریکہ‘ یورپ اور سلامتی کونسل کے دروازے پر مسلسل دستک دے رہی ہیں۔ وادی کشمیر مسلسل آگ میں جل رہی ہے۔ خون میں نہا رہی ہے‘ عزتیں لٹ رہی ہیں‘ نہ صرف نوجوان بلکہ بچے‘ بوڑھے اور صنف نازک تک کو عقل و فکر سے بالا اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن انسانی حقوق کے دعوے داروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بوسنیا‘ کسووا اور چیچنیا کے ہاں جس قدر انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اس کی مثال چشم فلک نے بھی شاید نہ دیکھی ہو۔ آج تک اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں۔ بایں ہمہ پوری دنیا پر سکوت و جمود طاری ہے۔
اور یہ فلسطین ہے ۱۹۴۲ء کو انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا۔ پھر عالم عرب کے قلب میں اسرائیل ریاست قائم کر دی گئی جس کی درندگی ‘ بربریت کی خبریں آتی رہی ہیں۔ لیکن اب اکتوبر کے آغاز سے ٹینکوں‘ توپوں اور راکٹوں سے فلسطین کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آئے دن مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے لیکن افسوس بالائے افسوس کہ کسی کو بھی یہاں انسانی حقوق کی پامالی نظر نہیں آتی بلکہ روس ‘ امریکہ ‘ بھارت جب ذرا محسوس کرتے ہیں کہ عالم عرب خواب غفلت سے بیدار ہوا چاہتا ہے تو فوراً مذاکرات کا بگل بجا دیا جاتا ہے۔
خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر
پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری
تاکہ مسلمان سویا رہے اور ہم انسانی حقوق کے شور و ہنگامے میں اپنوں کے حقوق کا تحفظ اور مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو سر عام نیلام کرتے رہیں۔ ان واقعات میں خاص طور پر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جو لڑائی میں مقابلہ کر رہے ہیں ان کا قتل تو سمجھ میں آتا ہے لیکن تہی دست (خالی ہاتھ) غیر مسلح لوگوں کا خون بہانا‘ خواتین کی عزت کو تار تار کرنا‘ بچوں کو گولیاں کا نشانہ بنانا اور بوڑھوں تک کو ٹینکوں تلے روند دینا انتہائی بدبختی ‘ شقاوت قلبی اور حیوانیت و درندگی ہے۔
آئیے ذرا اسلامی تعلیمات‘ اسلامی نظام حیات‘ واقعات اور تاریخ اسلامی کے حوالے سے حقوق انسانی کا جائزہ لیں کہ اسلامی تعلیمات میں انسانیت و آدمیت کا کیا مقام ہے؟ اور حقوق انسانی کی کیا اہمیت و عظمت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں حقوق انسانی کا دائرہ بڑا وسیع ہے اسلام میں انسانی حقوق کا آغاز ایک فرد کی ذات سے ہوتا ہے اور پھر اس کا دائرہ پھیلنا شروع ہوتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یوں یہ دائرہ وسعت اختیار کرتے کرتے گھر‘ قرابت دار‘ پڑوس‘ محلہ ‘ شہر ‘ ملک اور پوری دنیا کے افراد انسانی تک وسیع ہوجاتا ہے۔ اسی طرح تمام آفاق سے سمٹتا سمٹتا ایک فرد کی ذات میں جمع ہو جاتا ہے۔ اسلام نے انسانی حقوق کو صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ حیوانات‘ چرند پرند‘ درند‘ جمادات‘ نباتات تک کے حقوق بیان کر دیے ہیں۔
امام الانبیاء ﷺ کی تعلیمات مین اونٹ‘ ہرن اور چڑیا کے لیے بھی فلاح و بہبود اور حسن سلوک کرنے کی ہدایات موجود ہیں۔ انسانوں کے لیے درجہ وار حقوق کی ایسی ترتیب قائم کر دی ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ حقوق سے خالی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ مرد و عورت‘ اپنے پرائے‘ چھوٹے بڑے‘ بیمار تندرست‘ امیر غریب‘ حاکم رعایا‘ بہن بھائی‘ ماں باپ‘ شوہر بیوی‘ قریبی‘ اجنبی‘ مسلم غیر مسلم‘ شہری دیہاتی‘ غلام آقا‘ مہمان میزبان اور یتیم ‘ بیوہ غرض معاشرے کے ہر فردکے حقوق کی ایسی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ ایسی حد بندی کسی دوسرے مذہب و ملت میں نہیں پائی جاتی۔ مذہبی درجہ وار حقوق کی ایسی تفصیل موجود ہے جبکہ اسلام نے نے تو انسان کو من حیث الانسان بڑی تکریم اور فضیلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے :
"اور ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواری دی۔ اور ہم نے ان کو صاف ستھری چیزوں کا رزق دیا اور ہم نے ان کو اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی۔" (بنی اسرائیل)
صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ اسلام میں انسانی خون کو انتہائی قیمتی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی فرد کسی دوسرے انسان کو ناحق موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو مذہب اسلام میں مناسب سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ قتل و خون بہانے کو مختلف صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے جس قسم کا قتل ہوگا اسی طرح کی سزا کا تعین ہوگا۔ اس کے بارے میں قصاص و دیت کے تفصیلی احکام قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ عذاب آخرت اس کے علاوہ ہے۔
اس سلسلے میں چند قرآنی ارشادات ملاحظہ فرمائیں:
"اے ایمان والو ! تم پر مقتولوں کے بارے میں برابری کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔" (البقرہ)
"جس نے کسی جان کو بلا عوض یا زمین میں فساد کرنے کے بغیر مار ڈالا۔ تو گویا اس نے سب لوگوں کو مار دیا اور جس نے ایک جان کو زندہ رکھا گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا۔" (المائدہ)
"اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا‘ مگر جائز صورت میں" (الانعام)
اس سلسلے میں امام الانبیاء ﷺ کے فرموادت کا مطالعہ کریں کہ آپ نے کس قدر اہمیت سے انسانی جان کے تحفظ کو بیان کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا :
"مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے تہہ و بالا ہونے سے بڑھ کر ہے۔"
اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل میں ایک لفظ سے مدد کرے گا تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر رحمت سے مایوس لکھا ہوگا۔
اسلام کی نظر میں کوئی جان بے وقعت اور بے قیمت نہیں ہے اور کسی کو رائیگاں اور فضول قرار نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ اگر کوئی لاش آبادی میں یا آبادی سے باہر اتنی دور پائی جائے کہ اگر کوئی شخص زور سے آواز لگائے تو وہاں تک اس کی آواز پہنچ سکے تو اس مقتول کے آس پاس قریبی آبادی پر اس کی ذمہ داری ڈالی جائے گی تا کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد بیدار مغز‘ حالات سے با خبر اور محلہ میں ہر کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ‘ خیر اندیش‘ بھلائی کا خواہاں بن کر رہے۔ کسی کو اپنے علاقے میں شر و فساد‘ دہشت گردی اور امن و امان برباد نہ کرنے دے اور رات کی تاریکی میں بھی معاشرہ دن کی روشنی کی طرح ہی بیدار محسوس ہو۔ چنانچہ اس لاش کے ورثہ مقتول کے مطالبے پر فقہی کاروائی پوری کر کے دیت دلائی جاتی ہے۔ اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ یہ قوانین تو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں اسلامی قوانین بین الاقوامی امن و سلامتی کے ضامن ہیں۔
آئیے ذرا ایک ہلکی سی جھلک آپ کو اقلیتوں کے حقوق کی دکھلائے جائیں۔ اسلامی معاشرہ میں جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال‘ عزت و آبرو کی حفاظت کو ضروری قرار دیا گیا ہے اسی طرح اقلیتوں اور غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت و نگرانی بھی اسلامی حکومت اور معاشرے پر ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا۔
"جو کوئی غیر مسلم پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے گا تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں دعوے دار ہوں گا۔"
جنگ بدر میں جو مشرکین قید ہوئے تھے سرکار دو عالم ﷺ نے ان قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا تھا اور آپؐ نے فرمایا تھا : "قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔"
خود قید ہونے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ پر آپؐ کے اس ارشاد کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرامؓ پہلے ہمیں کھانا کھلاتے تھے اگر کھانا بچ جاتا تو کھاتے ورنہ صرف کھجور پر ہی اکتفا کر لیتے تھے۔
یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے مکہ میں حضور پاک ؐ اور صحابہؓ کو اذیت و تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا۔ اب موقع تھا کہ صحابہ کرام ان سے اپنی مرضی کے مطابق بدلہ لے سکتے تھے لیکن یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنانا تو درکنار بلکہ ہر ممکن آرام کا خیال رکھا جاتا ہے۔
آج کے مہذب و متمدن اور ترقی یافتہ ہونے کے دعوے دار ملکوں سے ذرا پوچھیں کہ کیا وہ اپنے اسیروں کے ساتھ ایسے سلوک کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ ان ملکوں میں تو حال یہ ہے کہ آئے دن جیلوں میں قیدیوں کو اذیتیں دے کر ہلاک کرنے کی خبریں پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ‘ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ کتنے قیدی ہیں جن کو روزانہ انڈین جیلوں میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔
امریکہ اسامہ بن لادن کے بہانے افغانستان اور سوڈان میں میزائل پھینک کر کتنا جانی و مالی نقصان کر چکا ہے۔ اور مزید موقع کی تلاش میں ہے۔ اہل عراق کے لیے پابندیاں لگا کر معصوم عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ امریکہ فلسطین میں جو کھیل کھیل رہا ہے اب تو پوری دنیا اس سے واقف ہو چکی ہے۔ بایں ہمہ ایک ہی سانس میں مسلسل انسانی حقوق کے راگ بھی الاپ رہا ہے۔ جبکہ اسلام میں جنگی ہدایات‘ تعلیمات میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ لڑائی کے دوران کسی بچے‘ بوڑھے‘ عورت‘ راہب ‘ معذور اور بیمار کو قتل نہ کیا جائے۔ درختوں اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ غیر مسلموں کو ان کی زمینوں‘ گھروں اور عبادت گاہوں سے الگ نہ کیا جائے۔
دور فاروقی میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا فاروق اعظمؓ کو نماز کا وقت ہوگیا۔ جب آپ عیسائیوں کے مشہور گرجا گھر (قمامہ) کی سیر کر رہے تھے۔ عیسائی پادری نے کہا کہ یہیں نماز ادا فرما لیں۔ آپؓ نے یہ کہہ کر نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا کہ کہیں کل کو مسلمان میرے نماز پڑھنے کو بہانہ بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ لہذا میں اس میں نماز ادا نہیں کروں گا۔
حضرت ابو عبیدہؓ نے ملک شام کو فتح کیا تو غیر مسلم ابو عبیدہؓ کے سلوک اور اسلامی تعلیمات میں اپنے حقوق کی حفاظت کی ہدایات کو دیکھ کر مسلمانوں کے حامی و مددگار بن گئے۔
محمد بن قاسم فاتحانہ سندھ میں داخل ہوئے اور راجہ داہر قتل ہوگیا تو لوگ مارے ڈر اور خوف کے اپنے گھروں کو چھوڑکر بھاگ رہے تھے۔ اسی وقت محمد بن قاسم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی اپنی جان بچانے کے لیے جانا چاہتا ہے اسے جانے دیا جائے اور اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم کے اس اعلان سے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور لوگ بدستور اپنے ہی گھروں میں ٹھہر گئے اور جو بھاگ گئے تھے واپس آگئے۔
ولید بن عبد الملک نے اپنے دور خلافت میں جامع مسجد دمشق کا کچھ حصہ جبراً عیسائیوں کی جگہ پر تعمیر کر دیا تھا۔ جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو مسجد کے اس حصہ کو گرانے اور عیسائیوں کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بالاخر عیسائیوں کی مرضی سے معاملہ طے پا گیا تو مسجد کے اس حصہ کو باقی رہنے دیا گیا۔
بیت المقدس سیدنا فاروق اعظمؓ کے دور خلافت سے مسلمانوں کے قبضہ میں چلا آرہا تھا۔ ۴۹۲ھ میں جب عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کر لیا تو چند سال میں فلسطین کا بڑا حصہ ان کے تصرف میں آگیا۔
انگریز مورخ لین پول لکھتا ہے :
"بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ پر صلیبی عیسائیوں نے ایسا قتل عام مچایا کہ ان صلیبوں کے گھرڑے جو مسجد عمر سوار ہوگئے گھٹنوں گھٹنوں خون کے چشمے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو دیواروں سے دے مارا یا ان کو دیواروں سے پھینک دیا گیا۔
اس کے بالمقابل جب ۵۸۳ء کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا اور ۹۰ سال بعد بیت المقدس کو فتح کرنے کی آرزو پوری ہوئی۔
ابن شداد لکھتے ہیں کہ ہر طرف دعا و تہلیل و تکبیر کا شور بلند تھا۔ ۹۰ برس بعد جمعہ کی نماز ہوئی۔ صلیب اتار دی گئی۔ اسلام کی فتح مندی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا عجیب منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔
بہرحال اسلام میں انسانی حقوق کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی مثال کسی مذہب و ملت ‘ تہذیب و تمدن‘ اور نظام و دستور میں نہیں ملتی۔ اسلامی تاریخ ایسے حقائق و مشاہد سے بھری پڑی ہے۔
انہیں چشم روشن اور دل زندہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین
سرکاری حج پالیسی اور حجاج کو درپیش مشکلات ۔ چیف ایگزیکٹو کے نام ایک مکتوب
مولانا محمد عبد العزیز محمدی
- بخدمت جناب عزت مآب جنرل پرویز مشرف ‘ چیف ایگزیکٹو پاکستان (اسلام آباد)
- بخدمت جناب وزیر حج و امور مذہبیہ پاکستان(اسلام آباد)
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ۔ مزاج گرامی ؟ ۔ امید ہے طبیعت بعافیت ہوگی۔
چند ایک معروضات پیش خدمت ہیں۔ حجاج کرام کو ہر سال پیش آمدہ مشکلات و مسائل وقتاً فوقتاً اخبارات اور قومی جرائد میں آتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں روزنامہ جنگ کی طرف سے جنگ فورم میں منعقدہ مذاکرہ کے مطالعہ کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب کی توجہ چند ایک تجاویز کی طرف خصوصیت سے مبذول کرائی جائے جن پر سنجیدگی سے غور کر کے انہیں قابل عمل بنا دیا جائے تو ان شاء اللہ امید ہے کہ کافی حد تک حجاج کرام کی شکایات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جناب ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ان تجاویز کو بیوروکریسی کی روایتی سازش اور دست برد سے بچا کر عملاً نافذ کرنے کے لیے ذاتی و سرکاری ذرائع بروئے کار لائیں۔
۱۔ جناب والا ‘ حجاج کرام کے لیے رہائش ‘ معلم کا انتخاب اور مکہ سے منیٰ ‘ عرفات‘ مزدلفہ آمد و رفت ٹرانسپورٹ کا انتظام حجاج کرام کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے اور ان کے لیے لازمی کٹوتی کو ختم کر دیا جائے۔
۲۔ بھارت غیر مسلم حکومت ہونے کے باوجود اپنے حجاج کرام سے درخواست کے ساتھ صرف پانچ ہزار روپے لیتی ہے۔ اور باقی رقم بعد میں جمع کرائی جاتی ہے جبکہ پاکستانی حکومت ہر سال حجاج کرام سے پوری رقم ۸ ماہ قبل جمع کراتی ہے جو حجاج کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ (یہ بہانہ کہ ہمیں سعودی حکومت کو بلڈنگ کے لیے ۲۳ فیصد ایڈوانس دینا پڑتا ہے‘ اسے آڑ بنا کر حجاج کرام سے پوری رقم اتنا عرصہ قبل لے لینے کا کوئی جواز نہیں) نیز بھارت اپنے حجاج کو سب سڈی دیتا ہے۔ جبکہ پاکستان ہر سال رقم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ حجاج کرام سے پہلے کی طرح ایک صد روپے کے فارم یا ایک چوتھائی رقم ایڈوانس لے لی جائے اور بقایا رقم حج سے دو تین ماہ قبل جمع کرائیجائے اس جائز اور مبنی بر حقیقت مطالبے کو مذہبی امور کے ناخدا سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آئندہ حج قومی کانفرنس کے موقع پر سب سے پہلے یہی مسئلہ زیر بحث لایا جائے اور رائے عامہ کا احترام کیاجائے۔
۳۔ جناب والا حج پالیسی پہلے سے تیار ہوتی ہے جسے حج بیورو کریسی دفتروں میں بیٹھ کر تیار کرتی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ کانفرنس کے موقع پر کئی باتوں کا جواب وہاں کے ذمہ دار یہ دیتے ہیں کہ یہ حج پالیسی میں نہیں ہے‘ کانفرنس تو اب ہو رہی ہے‘ پالیسی پہلے کس طرح طے ہوگئی؟ حج قومی کانفرنس رسمی‘ روایتی اور مہمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے محض ایک دھوکہ ہے۔ عوامی تجاویز کو در خور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ کانفرنس کے موقع پر مختلف کمیٹیوں کی تشکیل اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ طے شدہ ٹارگٹ کے حصول کے علاوہ عوامی تجاویز کو ضیاع وقت سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ اس دھوکہ دہی سے نجات دلا کر عوامی تجاویز کو قابل عمل بنایا جائے۔ وزارت مذہبی امور کے عملہ کی کارکردگی یہ ہے۔ ہماری ایک جوائنٹ درخواست (اپنے انتظام اور اپنی گاڑی سے چند احباب کا ایک گروپ حج پر لے جانے کے سلسلے میں) ڈائریکٹر مذہبی امور صوبہ سرحد نے اپنے مکتوب No 2(11)/94-DH(G)/962-63 Peshawar مورخہ ۲ دسمبر ۱۹۹۸ء سیکشن آفیسر (p.w) وزارت مذہبی امور کو بھیجی تھی۔ آج عرصہ دو سال کے بعد ہم ابھی تک جواب کے انتظار میں ہیں۔ متعلقہ افسران کو جواب دینے کی فرصت نہیں ملی یا جواب کی زحمت گوارا نہیں کر رہے یا ریکارڈ اتنا صاف ہے کہ درخواست ہی گم ہوگئی ۔
۴۔ حج و عمرہ کے لیے (Land Route) خشکی کے راستے ٹرانسپورٹ کارواں بھیجے جائیں۔ اس سے نوجوانوں میں شوق بڑھے گا۔ راستے میں مقدس مقامات کی زیارت ہوگی۔ P.I.A کا بوجھ کم ہوگا اور گزشتہ سال کی طرح P.I.A کی طرف سے پیدا شدہ مشکل صورت حال کا اعادہ نہیں ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کا یہ عذر لنگ کب تک چلے گا کہ (Land Route) حج پالیسی میں نہیں ہے۔ آخر پالیسی میں کب آئے گا۔ کون پالیسی بنائے گا اور کب تک من مانی چلے گی۔ اگر حکومت سرکاری طور پر حج کارواں نہیں بھیج سکتی تو کم از کم اپنے طور پر پرائیویٹ قافلے By Road جانا چاہیں تو انہیں سہولیات‘ ویزہ کے حصول کے لیے سرکاری طور پر تعاون اور ضروری کارروائی کے ساتھ ساتھ N.O.C دے دی جائے۔
۵۔ حج و عمرہ کے لیے بحری راستے نامعلوم وجوہ کی بنا پر بند کر دیے گئے۔ صرف یہ بہانہ کہ بحری جہاز ناکارہ ہوگئے ہیں‘ بیک وقت سب کیسے ناکارہ ہوگئے۔ اس سلسلے میں تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ اگر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن والے بیک وقت بحری جہازوں کے ناکارہ ہونے میں اپنی غفلت و کوتاہی کی سزا غریب لوگوں کو دینے اور پاکستانی بندرگاہوں کی افادیت و اہمیت ختم کرنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو پرائیویٹ جہاز رانی کی حوصلہ افزائی کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کو رائیلٹی اور خصوصی رعایات دی جائیں تا کہ سمندری صنعت کو فروغ ہو اور حج و عمرہ کے لیے پہلے کی طرح بحری راستوں کو بھی اختیار کیا جا سکے۔
۶۔ حج بدل در حقیقت حج فرض ہی کی طرح ہے اس لیے حج بدل والوں کو مخصوص کوٹہ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔
۷۔ حاجیوں کو بلڈنگ مافیا کی رشوت‘ ناواقف اور سفارشی عملہ سے نجات دلائی جائے۔ حج کے نام پرناجائز منافع خوری کا سد باب کیا جائے۔ جو رہائش ۶۰۰ ریال پر ملتی ہے اس کا کرایہ حاجیوں سے ۱۴۵۰ ریال لے لیا جاتا ہے۔یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ویسے بھی حج فارموں میں حجاج کے لیے رہائش کی درجہ بندی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کم سے کم ۸۰۰ ریال اور زیادہ سے زیادہ ۱۶۰۰ ریال لیے جانے کا کالم ہوتا ہے۔ مگر کسی حاجی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس درجہ کی رہائش میں ہے۔ ہر حاجی سے زیادہ سے زیادہ (maximum) کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ وہاں حاجی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ خدام الحجاج صرف فوجی اور سکاؤٹس بھیجے جاتے ہیں ۔ اگر پرائیویٹ طور پر حجاج کرام کی خدمت کرنے والی تنظیموں سے بھی خدام بھیجنے کے لیے ایک کوٹہ مقرر کیا جائے تو وہ اپنی ساکھ باقی رکھنے کی خاطر صحیح معنوں میں خدام فراہم کرتے ہوئے دیندار‘ محنتی اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے افراد مہیا کر سکیں گے ۔
۸۔ حاجی کیمپوں میں مستورات کے لیے پردے کا صحیح انتظام کیاجائے۔ پردے کے ریک (rack) اور کیبن بنائے جائیں تا کہ کوئی حاجی اپنے محرم‘ مستورات کو ملنا چاہیں تو بے پردگی کا احتمال نہ ہو‘ موجودہ صورت حال غیر تسلی بخش ہے۔ نیز حج و عمرہ کی پروازوں میں لیڈیز ایئر ہوسٹس کو ممنوع قرار دے کر سٹیورڈ مقرر کیے جائیں۔
۹۔ سرکاری سطح پر سعودی عرب کو آگاہ کیا جائے کہ بعض معلمین حجاج کے وقوف منیٰ و مزدلفہ کے حدود کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس سال وقوف منیٰ کے خیمے منیٰ کے علاوہ مزدلفہ کی حدود میں بھی نصب کرائے گئے تھے۔ حجاج کو حدود کا علم نہیں ہوتا اس لیے معلمین کو پابند کیا جائے کہ وقوف منیٰ ‘ مزدلفہ اپنی اپنی حدود میں کرائیں۔
۱۰۔ رمضان المبارک کے احترام میں عمرہ کے لیے P.I.A کی ٹکٹ میں دس ہزار روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں واپسی ٹکٹ اسلام آباد سے 28-27 ہزار ہوتی ہے جبکہ رمضان شریف میں 38-35 ہزار روپے کر دی جاتی ہے۔ نیز ایک اور مشکل درپیش ہے کہ ٹریول ایجنسیز اور P.I.A سٹاف والے ملی بھگت سے عمرہ والوں کے لیے جعلی سیٹ (O.K.) کرا لیتے ہیں‘ جب ویزہ لگ کر آجاتا ہے تو سیٹ کی تصدیق (confirmation ) سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ وہ تو صرف ویزہ کے حصول کے لیے O.K کرائی تھی۔ عازمین مجبور ہوتے ہیں۔ آخر تک پریشان رہتے ہیں ۔ بالاخر P.I.A اور ٹریول ایجنسیز کی بلیک میلنگ اور اضافی اخراجات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کھلے فراڈ سے نجات دلائی جائے۔
۱۱۔ حاجی کیمپوں میں کسٹم سٹاف حجاج کی بعض استعمال کی چیزوں مثلاً ٹوتھ پیسٹ‘ تیل‘ صابن‘ ادویات وغیرہ کو ممنوع قرار دے کر حاجیوں کے ورثا کو واپس دینے کی بجائے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بعد میں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہے۔ اگر وہ اشیاء واقعی ممنوع ہیں تو حجاج کے ورثا کو واپس کر دی جائیں۔
یہ چند ایک گزارشات میں نے عرض کر دی ہیں جو وزارت مذہبی امور کی دانستہ یا غیر دانستہ غلط حکمت عملی کی وجہ سے حجاج کے لیے پریشان کن ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اختیارات دیے ہیں‘ اللہ پاک کے مہمانوں کو ان مشکلات سے نجات دلا کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت مطہرہ کی بالادستی قائم کرنے اور ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
خادم العلماء والحجاج : (مولانا) محمد عبد العزیز محمدی ‘خطیب جامع مسجد (امان) اسلامیہ کالونی ‘ ڈیرہ اسماعیل خان
کراچی میں حافظ الحدیث کانفرنس کا انعقاد
ادارہ
شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت ‘ اسلامی نظام کے نفاذ‘ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور باطل نظریات و افکار کے تعاقب کے لیے جدوجہد میں گزار دی اور ان کی بھرپور زندگی علماء کرام اور دینی کارکنوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز علماء کرام نے گزشتہ دنوں جامعہ انوار القرآن آدم ٹاؤن نارتھ کراچی میں حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی رحمہ اللہ علیہ کی یاد میں پاکستان شریعت کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی "حافظ الحدیث کانفرنس" سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
کانفرنس کی پہلی نشست حضرت مولانا مطیع الرحمن درخواستی اور دوسری نشست کی صدارت پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا فداء الرحمن درخواستی نے کی۔ جبکہ کانفرنس سے سپاہ صحابہؓ کی سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا ضیاء القاسمی‘ جمعیت علماء اسلام (س) کے قائم مقام مرکزی امیر مولانا قاضی عبد اللطیف‘ پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی‘ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ڈاکٹر فضل احمد‘ مولانا اسعد تھانوی‘ مولانا بشیر احمد شاد‘ مولانا سیف الرحمن ارائیں‘ مولانا عبد الرشید انصاری‘ شیخ الحدیث مولانا زرولی خان‘ مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی‘ مولانا قاری اللہ داد‘ شاعر اسلام سید سلمان گیلانی‘ قاری عبد الکریم اور قاری محمد اکبر مالکی نے خطاب کیا۔ کانفرنس صبح ساڑھے دس بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک جاری رہی اور اس میں کراچی اور دیگر شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام‘ دینی کارکنوں او رطلبہ نے شرکت کی۔
مولانا ضیاء القاسمی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ علیہ نے زندگی بھر محنت اور جدوجہد کے ساتھ دین کا جو گلشن آباد کیا وہ ہم سب کی امیدوں کا مرکز ہے اور ہم اس کی ہمیشہ آبادی کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ اہل حق کے قافلہ سالار تھے اور انہوں نے حق پرست علما اور کارکنوں کی ہر دور میں سرپرستی کی۔
مولانا قاضی عبد اللطیف نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی نے ملک میں نفاذ اسلام کی جدوجہد کی قیادت کی اور ان کی سربراہی میں اہل حق کے قافلہ نے ربع صدی سے زیادہ عرصہ تک نفاذ شریعت کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس لیے آج ان کا سب سے بڑا ورثہ یہی جدوجہد ہے اور ہم سب کو اس جدوجہد میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج فوجی حکومت کو این جی اوز اور لا دین عناصر نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور یہ این جی اوز پاکستان کی اسلامی حیثیت کے خاتمہ کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے وجود اور اس کے نظریاتی تشخص کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اس لیے علماء کرام اور دینی حلقوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اس خطرے کا مقابلہ کریں اور ملک کی اسلامی حیثیت اور قومی وحدت کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے گریز نہ کریں ۔انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کے اسلامی دستور کے مخالف قوم پرست سیاست دان لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے دستور کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور اس کے خاتمہ کے لیے مطالبات کر رہے ہیں جو خطرے کا الارم ہیں کیونکہ اگر خدانخواستہ ۷۳ کا دستور ختم ہوگیا تو اس ملک میں پھر کسی آئین پر قومی اتفاق رائے حاصل نہیں کیا جا سکے گا اور قومی وحدت خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بین الاقوامی ایجنڈے کے سب سے بڑے اہداف تین ہیں۔ ایک یہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کیا جائے‘ دوسرا یہ کہ پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا جائے اور تیسرا یہ کہ فوج سے عوام کو متنفر کر کے ملک کے دفاع کی قوت کو غیر موثر بنا دیا جائے۔ اس ایجنڈے پر تیزی سے عمل ہو رہا ہے اور مختلف شعبوں میں فوج کو براہ راست ملوث کرنے سے لے کر اشیاء صرف کے نرخوں میں اضافے اور ضلعی حکومتوں کے نام سے نیم خود مختار ریاستوں کے قیام اور عورتوں کی آزادی کے بہانے خاندانی نظام کی تباہی کی مہم تک منصوبوں پر تسلسل کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی حلقوں اور جماعتوں کی قیادتیں سرجوڑ کر بیٹھیں اورملکی وحدت اور اسلامی دستور کے تحفظ کے لیے متحد ہو جائیں۔
مولانا زاہد الراشدی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی اہل حق کی روایات کے امین تھے۔ انہوں نے اپنے عظیم اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے تحفظ و ترویج کے لیے ہر مورچہ پر جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا درخواستی کی پون صدی سے زیادہ عرصے پر محیط جدوجہد کے سات اہداف سب سے نمایاں تھے جن کے لیے وہ ہر وقت سرگرم عمل رہتے تھے اور اپنے ساتھیوں اور کارکنوں کو سرگرم عمل رہنے کی تلقین کرتے تھے۔
پہلے نمبر پر وہ ملک میں نفاذ شریعت کے نفاذ کے خواہاں تھے اور انہوں نے مسلسل پینتیس برس تک جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر کی حیثیت سے اس جدوجہد کی راہنمائی کی۔ وہ اپنے ہر عقیدت مند اور شاگرد سے عام اجتماعات میں اس بات کا حلف لیا کرتے تھے کہ وہ زندگی بھر نفاذ شریعت کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا۔
دوسرے نمبر پر وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ منکرین ختم نبوت کا تعاقب‘ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت و تشریح اور علماء کرام کو اس محنت کے لیے تیار کرنا ان کا خصوصی موضوع تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی مہمات کی عملی طور پر بھی قیادت کی۔
تیسرے نمبر پر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت و عقیدت کا بطور خاص درس دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرامؓ کے واقعات بیان کرتے‘ ان کی محبت اور عقیدت کو ابھارتے‘ ان پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیتے اور ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے علماء کرام اور کارکنوں کو جدوجہد پر آمادہ کرتے تھے۔
چوتھے نمبر پر جہاد حضرت درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیانات کا خاص موضوع ہوا کرتا تھا۔ جب افغانستان کے جہاد کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ اس دور میں بھی جہاد کے فضائل بیان کرتے‘ قرون اولیٰ کے واقعات سناتے اور اپنے شاگردوں اور سامعین کو جہاد کے لیے تیار کرتے تھے اور جب جہاد افغانستان عملاً شروع ہوا تو انہوں نے افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے کا طوفانی دورہ کر کے علماء کرام اور دیندار عوام کو افغان مجاہدین کی پشت پناہی کے لیے تیار کیا اور آخر دم تک افغان جہاد کی حمایت اور پشت پناہی کرتے رہے۔
پانچویں نمبر پر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے رابطہ اور تعلق کا سبق دیتے اور باطنی تزکیہ اور اصلاح کی طرف توجہ دلاتے تھے۔
چھٹے نمبر پر حضرت درخواستی کا خاص مشن ملک کے ہر حصے میں دینی مدارس کا قیام تھا‘ وہ جہاں جاتے دینی مدارس قائم کرنے کی تلقین کرتے‘ مدارس کے لیے چندہ اکٹھا کر کے دیتے اور ان مدارس کی عملی اور مالیاتی سرپرستی کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور انہی کے ذریعہ معاشرہ میں دین کی حفاظت ہوگی۔
ساتویں نمبر پر انہوں نے اہل حق کی مختلف جماعتوں کے درمیان مفاہمت و ارتباط کے لیے ہر دور میں کوشش کی‘ وہ علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والی ہر جماعت کو اپنی جماعت کہتے تھے اور سب جماعتوں کی سرپرستی کرتے ہوئے ان میں اتحاد و اشتراک کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
مولانا زاہد الراشدی نے کہا کہ دین کی جدوجہد کے یہ ساتوں محاذآج بھی موجود ہیں اور حضرت درخواستی ؒ کے ساتھ ہماری محبت و عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم ان محاذوں پر اسی طرح سرگرم عمل رہیں جس طرح ہمارے مرحوم اور مربی ہمیں سرگرم عمل رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔
مولانا بشیر احمد شاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت جن مدارس کے ذریعہ قائم ہوئی ہے‘ ان مدارس کا جال حضرت درخواستی ؒ نے ہی بچھایا تھا اور ان کی جدوجہد کے نتیجے میں ہی دنیا میں ایک بار پھر اسلامی نظام کے نفاذ کا مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت درخواستی ؒ کی جدوجہد جاری رہے گی اور ہم ان کے خدام کی حیثیت سے ان کے مشن کی تکمیل کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔
مقررین نے حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی خدمات‘ دینی جدوجہد اور ملی کارناموں کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی اوصاف ‘ کرامات اور نیکی و تقویٰ کے بیسیوں واقعات بیان کیے اور کہا کہ وہ اس صدی میں پرانے بزرگوں کی روایات اور اخلاق و عادات کا نمونہ تھے۔ جبکہ کانفرنس کے اختتام پر حضرت درخواستی ؒ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کی گئی۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’دارالعلم کی مطبوعات‘‘
معہد اللغۃ العربیۃ اور دارالعلم ۶۹۹ آب پارہ مارکیٹ اسلام آباد کے سربراہ مولانا محمد بشیر سیالکوٹی باذوق اہل حدیث عالم دین ہیں جو قادیانیت جیسے گمراہ گروہوں کے علمی و فکری تعاقب کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے مختلف مکاتب فکر میں باہمی رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ اور عربی زبان کی ترویج کے لیے مسلسل سرگرم عمل رہتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کی خدمات کو تمام دینی حلقوں میں احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
وہ ایک عرصہ سے اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں کہ دینی مدارس میں عربی زبان اور لغت اور ادب و انشاء کی تعلیم و تدریس کے لیے جدید اسلوب کو اپنایا جائے تا کہ سالہا سال تک ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور تدریسی خدمات سر انجام دینے والے اساتذہ میں عربی زبان میں تحریر و گفتگو کی صلاحیت کا جو خلا رہ جاتا ہے اور بری طرح محسوس ہوتا ہے اسے پر کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ندوۃ العلماء لکھنو طویل مدت سے مصروف کار ہے جس کے مثبت نتائج سب کے سامنے ہیں لیکن تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اس رخ پر کوئی موثر کام نہیں ہو سکا اور ہمارے خیال میں مولانا محمد بشیر سیالکوٹی اسی مہم کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں جس کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں مختلف طبقات کے لیے عربی کلاسوں کے اجرا کے علاوہ نصابی ضروریات کے لیے کتابوں کی تدوین و اشاعت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے جن میں سے دو کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔
(۱) مفتاح الانشاء حصہ اول میں اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ کو عربی ترجمہ اور تحریر و انشاء سکھانے کے لیے جدید اسلوب کے مطابق خاصا مفید مواد جمع کر دیا گیا ہے۔
(۲) اساس الصرف میں علم صرف کے ضروری قواعد کو نئے اسلوب سے مرتب کر کے ضروری تمرینات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
(۳) اقرأ کے نام سے عربی ریڈر چار حصوں میں ہے جس میں کثیر الاستعمال عربی الفاظ و محاورات کا اچھا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ مولانا محمد بشیر سیالکوٹی کی کوشش ہے کہ سعودی عرب کی وزارت تعلیم نے عربی نہ بولنے والوں کے لیے دروس اللغۃ العربیۃ کے نام سے تین حصوں میں جو نصابی کتاب شائع کی ہے دینی مدارس اسے بھی اپنے نصاب میں شامل کریں تا کہ طلبہ میں جدید عربی کو سمجھنے اور اس میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو اور ہماری معلومات کے مطابق اہل حدیث مکتب فکر کے وفاق المدارس السلفیہ پاکستان نے ان کی تجاویز کو منظور کرتے ہوئے عربی زبان کی تعلیم و تدریس کے نصاب و اسلوب میں ضروری تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے جو ہمارے خیال میں اس سمت میں ایک مثبت پیش رفت ہے۔
ہم اصولی طور پر مولانا موصوف کے اس موقف سے متفق ہیں کہ علما اور طلبہ میں جدید عربی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تعلیم و تدریس کے جدید اسلوب کو اختیار کرنا ضروری ہے ۔اس لیے دینی مدارس اور ان کے وفاقوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس اہم ضرورت کا احساس کریں اور اس بری طرح محسوس ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے ندوۃ العلماء لکھنو کے نصاب‘ مولانا محمد بشیر سیالکوٹی کی تجاویز اور دیگر متعلقہ ماہرین کی آرا کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری اقدامات سے گریز نہ کریں۔
’’قرآن پاک کے نئے سائنسی معجزات‘‘
ڈاکٹر سلطان بشیر محمود صاحب اور میجر (ر) امیر افضل خان صاحب نے اپنی اس مشترکہ کاوش میں مختلف سائنسی اصولوں اور ضابطوں کے حوالہ سے قرآن کریم کے متعدد مضامین اور معارف کو نئے رنگ میں پیش کیا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں مختلف حلقوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات اور مغالطوں کا جواب دیا ہے۔ دو سو سے زائد صفحات کی یہ کتاب خوبصورت ٹائٹل اور مضبوط جلد کے ساتھ القرآن الحکیم ریسرچ فاؤنڈیشن 60/B ناظم الدین روڈ F-8/4 اسلام آباد نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت ایک سو روپے ہے۔
’’قیامت اور حیات بعد الموت‘‘
یہ کتاب ڈاکٹر سلطان بشیر محمود صاحب کی تصنیف ہے جسے اردو میں میجر (ر) امیر افضل خان صاحب نے پیش کیا ہے۔ اس میں قیامت اور حیات بعد الموت کے بارے میں اسلامی عقائد اور قرآن وسنت کی تشریحات کی سائنسی انداز میں وضاحت کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ساڑھے پانچ سو سے زائد صفحات پر مشتمل اس ضخیم اور مجلد کتاب کی قیمت تین سو روپے ہے اور اسے مندرجہ بالا ایڈریس سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
’’اسماء اللہ عز و جل‘‘
جناب رشید اللہ یعقوب نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے اسماء گرامی کے بارے میں قرآن کریم‘ احادیث نبویہ اور بزرگان دین کے اقوال و فرمودات کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے جو ان کے حسن ذوق کا آئینہ دار ہے اور اصحاب ذوق کے لیے بیش بہا تحفہ ہے۔
عمدہ کتابت و طباعت‘ خوبصورت ٹائٹل اور مضبوط جلد کے ساتھ آرٹ پیپر پر شائع ہونے والی یہ کتاب اڑھائی سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے جسے صدقہ جاریہ کے طور پر شائع کیا گیا ہے اور اسے رحمۃ للعالمین ریسرچ سنٹر مکان نمبر 8 زمزمہ سٹریٹ نمبر 3 زمزمہ کلفٹن کراچی 75600 سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
’’نسخہ سکون‘‘
ماہنامہ الہلال مانچسٹر کے مدیر مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی نے بیماریوں اور ان کے جسمانی و روحانی علاج کے بارے میں ضروری دینی معلومات اور احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ ماثور دعاؤں کا ایک انتخاب اس کتابچہ میں پیش کیا ہے جو مختلف بیماریوں کے بارے میں جناب نبی اکرم ﷺ حضرات صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؒ سے منقول ہیں۔ یہ کتابچہ ادارہ اشاعت الاسلام برطانیہ نے شائع کیا ہے اور اسے مندرجہ ذیل ایڈریس سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ P.O. Box 36 Manchester M16 7AN (UK)
’’صمصام الاسلام‘‘
میانمار (برما) کے مسلم اکثریت کے صوبہ اراکان کے مسلمان ایک عرصہ سے برمی حکومت کے مظالم کا شکار اور دینی آزادی اور تشخص کے تحفظ کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں‘ حضرت مولانا حافظ محمد صدیق اراکانی اس جدوجہد کے اہم راہ نماؤں میں سے ہیں جنہوں نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت اس کتابچہ میں جہاد کی اہمیت اور اس کے احکام و مسائل کی وضاحت کے ساتھ ساتھ جہادی تحریکات کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے اور جہاد سے متعلقہ امور پر علمی انداز سے بحث کی ہے۔
سوا سو سے زائد صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ حرکۃ الجہاد الاسلامی اراکان نے شائع کیا ہے اور اسے مصنف سے جامع احتشامیہ جیکب آباد کراچی سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
فروری ۲۰۰۱ء
مشکلات ومصائب میں سنت نبویؐ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(مدیر ’’الشریعہ‘‘ مولانا زاہد الراشدی نے ۱۲ جنوری سے ۲۱ جنوری ۲۰۰۱ء تک متحدہ عرب امارات کا تبلیغی دورہ کیا اور مختلف اجتماعات سے خطاب کرنے کے علاوہ سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں کیں اور متعدد علمی ودینی مراکز میں گئے۔ انہوں نے یہ دورہ جمعیۃ طلباء اسلام پاکستان کے سابق راہ نما جناب محمد فاروق شیخ اور جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ متحدہ عرب امارات کے سیکرٹری اطلاعات حافظ بشیر احمد چیمہ کی دعوت پر کیا اور دبی ، شارجہ، عجمان، ام القوین، راس الخیمۃ اور الفجیرۃ کی ریاستوں میں احباب سے ملاقاتیں کیں۔ اتفاق سے جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمن صاحب بھی ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھے چنانچہ دونوں راہ نماؤں نے دبی کی مسجد الغریر، مسجد الرفاعۃ اور مسجد بلال بن رباحؓ میں عام اجتماعات سے خطاب کیا اور حافظ بشیر احمد چیمہ کی طرف سے دیے گئے عصرانہ میں شرکت کی۔ مسجد بلال بن رباحؓ میں عام اجتماع سے مولانا زاہد الراشدی کے خطاب کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ادارہ)
بعد الحمد والصلوۃ۔ آج کے اس اجتماع سے جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمن تفصیلی خطاب کریں گے۔ ان سے قبل مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کو کہا گیا ہے، ا س لیے بطور تمہید چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ مجھ سے پہلے ہمارے فاضل دوست مولانا مفتی عبد الرحمن نے اپنے خطاب میں افغانستان کی طالبان حکومت کا ذکر کیا ہے اور اسے درپیش مشکلات کا حوالہ دیا ہے۔ بلا شبہ ’’طالبان‘‘ آج کے دور کا مظلوم ترین طبقہ ہے جس کے خلاف کفر ونفاق کی پوری دنیا متحد ہو گئی ہے اور انہیں عالمی استعمار کے سامنے جھکانے یا مٹا دینے کے لیے منصوبے بن چکے ہیں۔
طالبان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کا صرف نام نہیں لیتے بلکہ اپنے ملک میں اسلامی احکام وقوانین کو عملی طور پر نافذ بھی کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں وہ کسی قسم کے بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا اصل جرم یہی ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف پابندیوں اور ان کی اقتصادی ناکہ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اس سے قبل بھی اہل حق اس قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے آ رہے ہیں حتی کہ خود نبی اکرم ﷺ کو بھی مکہ مکرمہ کے کفار کی طرف سے اس قسم کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تھا جب قریش کے باقی خاندانوں نے بنو ہاشم سے مطالبہ کیا تھا کہ محمد ﷺ کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیا جائے لیکن بنو ہاشم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے مل کر بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور جناب نبی اکرم ﷺ اپنے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں تین سال تک محصور رہے۔
کفار کی طرف سے ان کے خلاف یہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں کہ ان کے ساتھ لین دین نہیں ہوگا، ان سے رشتہ داری قائم نہیں کی جائے گی، ان کے پاس خوراک وغیرہ کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی اور ان کی معاشی ناکہ بندی ہوگی۔ اس دوران نبی اکرم ﷺ اور ان کے ساتھیوں کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کا اندازہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارے کیا کرتے تھے اور راستے میں پڑا ہوا خشک چمڑا اٹھا لیتے تھے اور اسے گرم پانی میں نرم کر کے چبا کر نگل لیا کرتے تھے۔
سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وادی میں بھوکے بچے جب روتے چلاتے تو ارد گرد گھومنے والے مشرکین یہ آوازیں سن کو خوش ہوا کرتے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ نبی اکرم ﷺ اور ان کے خاندان کو محصور رہنا پڑا لیکن مشرکین کی عائد کردہ یہ پابندیاں اسلام کا راستہ نہ روک سکیں اور اسلام کی دعوت وتبلیغ کا عمل نہ صرف جاری رہا بلکہ اس دوران حضرت ابو ذر غفاریؓ اور بہت سے دیگر حضرات نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کو اندازہ ہوگیا کہ ان کی پابندیاں اور ناکہ بندی تین سال گزرنے کے باوجود کارگر نہیں ہو رہی تو کچھ سمجھ دار مشرکین نے آگے بڑھ کر وہ معاہدہ ختم کرا دیا۔ اس لیے آج بھی یہ پابندیاں اسلام کا راستہ نہیں روک سکیں گی اور اگر طالبان حکومت اپنے مشن اور پروگرام پر استقامت کے ساتھ گامزن رہی تو پابندیاں لگانے والوں کو بہت جلداندازہ ہو جائے گا کہ ان کا فیصلہ کس قدر غلط تھا۔
میں اس موقع پر اس صورت حال کے حوالہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکلات ومصائب کے بارے میں اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اور اس سلسلہ میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اس پر سیرت نبوی سے دو واقعات پیش کروں گا تاکہ یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ مشکلات ومصائب کے دور میں سنت نبوی کیا ہے۔
ایک واقعہ تو اس وقت کا ہے جب نبی اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت ظاہری کیفیت یہ تھی کہ خود اپنی جان کے تحفظ کا مسئلہ درپیش تھا، رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، سفر کے لیے عام راستہ اختیار نہیں کیا تھا بلکہ خفیہ راستے سے سفر کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے ہمراہ تین دن تک غار ثور میں روپوش رہے اور راستہ میں چلتے ہوئے کسی کو اپنے نام بتانے میں بھی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہ تو ظاہری کیفیت تھی کہ بظاہر جان کا بچانا مشکل ہو رہا تھا لیکن اسی دوران سراقہ بن مالکؓ جناب نبی اکرم ﷺ کو راستہ میں ملے اور پکڑنے میں ناکام ہو کر امان چاہی تو نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ’’سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسری بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں‘‘
یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے قدرت کے ساتھ ساتھ حکمت کا بھی اظہار تھا جس میں ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ ایک یہ کہ خدائی فیصلے ظاہری حالات پر نہیں ہوتے۔ ظاہری حالات جس قدر بھی ناموافق ہوں، اگر مسلمان کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہے اور اس کا ایمان ویقین پختہ ہے تو ظاہری حالات کی ناسازگاری اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ مسلمان کو ظاہری حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہئے، مشکلات کتنی ہی کیوں نہ ہوں ،اسے اپنا ہدف سامنے رکھنا چاہئے اور ٹارگٹ میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہئے۔ اب دیکھئے کہ جناب نبی اکرم ﷺ ظاہری طور پر کس حال میں ہیں کہ چھپ کر اور جان بچا کر مدینہ منورہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نظر کہاں ہے؟ کسری کے کنگنوں پر جو اس وقت کی ایک بڑی سلطنت کا حکمران تھا اور سراقہ بن مالکؓ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اسے کسری کے کنگن پہنائے جائیں گے اور پھر یہ صرف ایک وقتی بات نہیں تھی بلکہ پیش گوئی تھی جو حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ کے دور خلافت میں فارس فتح ہوا، کسری کے شاہی خزانے غنیمت کے مال میں مدینہ منورہ آئے، ان میں وہ کنگن بھی تھے جو کسری بادشاہ دربار میں پہنا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے کسری کے کنگن انہیں پہنائے کہ اگرچہ سونے کے کنگن پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے لیکن جناب نبی اکرم ﷺ کی پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے میں یہ کنگن کچھ دیر کے لیے تمہیں پہنا رہا ہوں۔ اس طرح جناب نبی اکرم ﷺ نے ہمیں سبق دیا کہ مشکلات ومصائب اور حالات کی ناساز گاری سے گھبرا کر مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہئے اور اپنے ہدف اور ٹارگٹ میں کوئی کمزوری نہیں دکھانی چاہئے۔
دوسرا واقعہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ مسلمانو ں کے مقابلہ میں بدر و احد کی جنگ میں ناکام ونامراد ہو کر قریش مکہ نے یہ بات سمجھ لی کہ وہ اکیلے جناب نبی اکرم ﷺ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے عرب قبائل سے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے خلاف ان کا متحدہ محاذ بنوایا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف یلغار کر دی۔ یہ غزوۂ احزاب کی بات ہے جسے غزوۂ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک طرف عرب قبائل کا بہت بڑا متحدہ محاذ تھا اور دوسری طرف جناب نبی اکرم ﷺ اور ان کے ساتھی تھے جن کی تعداد چھوٹے بڑے سب ملا کر ڈیڑھ ہزار کے قریب تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورہ سے خندق کھودنے کا پروگرام بنایا اور خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دن رات خندق کھودنے میں مصروف رہے۔ قرآن کریم نے سورۃ الاحزاب میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پر چاروں طرف سے لشکر چڑھ دوڑے تھے، جب تمہاری آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئی تھیں، جب خوف کی شدت سے تمہارے دل سینوں سے اچھل کر حلق میں پھنس گئے تھے، جب تم اللہ تعالی کی مدد کے بارے میں گمانوں کا شکار ہونے لگے تھے، جب مومنوں کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا اور جب ان پر شدید زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔
یہ اس وقت کی ظاہری کیفیت تھی جس کا نقشہ قرآن کریم ان الفاظ میں کھینچ رہا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ بہت سے خندق کھودنے والوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور بعض لوگوں نے بھوک کی شدت سے یپٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے حتی کہ ایک صاحب نے جناب نبی اکرم ﷺ کو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ اس نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے تو نبی اکرم ﷺ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھا دیا جہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس صورت حال میں جب ظاہری طور پر سخت مایوسی اور شدید خوف کی کیفیت مدینہ منورہ کی آبادی کا احاطہ کیے ہوئے تھی، جناب نبی اکرم ﷺ سے خندق میں ایک چٹان کے سخت ضربوں کے باوجود نہ ٹوٹنے کی شکایت کی گئی، چنانچہ نبی اکرم ﷺ خود تشریف لے گئے اور کدال کی ایک ہی ضرب سے چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب آپ نے کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو وہاں سے چمک اٹھی اور جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ’’مجھے اس چمک میں قیصر وکسری کے محلات دکھائی دیے ہیں‘‘
ظاہری کیفیت دیکھئے کہ خوف اور مایوسی کا کیا عالم ہے؟ اور اس حالت میں نظر کی بلندی ملاحظہ کیجئے کہ اس وقت کی دو سب سے بڑی سلطنتوں کے شاہی محلات دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں تھی بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے خوش خبری تھی اور یہ سبق تھا کہ ظاہری حالات سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، اس پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مشن پر گامزن رہو اور اپنے ٹارگٹ اور ہدف میں کوئی کمزوری نہ آنے دو۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر سازوسامان اور لشکر کی کثرت کے باوجود قبائل عرب کی یہ یلغار ناکام ہوئی اور اللہ تعالی نے جناب نبی اکرم ﷺ کو نہ صرف فتح عطا فرمائی بلکہ اس پیش گوئی کے مطابق قیصر وکسری کے شاہی محلات بھی اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کو عطا فرمائے۔
قرآن کریم میں ہے کہ آزمائش اور ابتلا کے اس سخت ترین دور کے بعد غزوۂ احزاب میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ ہوا کوتیز کر دیا اور غیبی لشکر آسمان سے اتارے جنہوں نے محاصرہ کرنے والے کافروں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا اور وہ کوئی مقصد حاصل کیے بغیر ناکام واپس لوٹ گئے۔
اس لیے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہئے کہ طالبان کی اسلامی حکومت اگر اسلام کے مکمل اور عملی نفاذ کے مشن پر قائم رہتی ہے اور ظاہری حالات کی ناسازگاری سے خوفزدہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے بھی غیب کی قدرتیں حرکت میں آئیں گی اور امریکہ کی قیادت میں عالمی استعمار کا ان کے خلاف متحدہ محاذ اسی طرح ناکام ہوگا جس طرح جناب نبی اکرم ﷺ کے خلاف قبائل عرب کا اتحاد ناکام ہو گیا تھا البتہ ہمیں اس حوالہ سے اپنی ذمہ داریوں پر ضرور نگاہ رکھنی چاہئے کہ اپنے مظلوم طالبان بھائیوں کی اس مشکل وقت میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں اور ان کا ہاتھ کس طرح بٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقہ سے نباہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔
خلافت اسلامیہ کی اہمیت
الشیخ عمر بکری محمد
اپنی پوری تیرہ سو سالہ تاریخ میں اسلامی نظام (خلافت) نے انسانی جدوجہد کے ہر پہلو سے، خواہ وہ معاشی ہو، جنگی ہو یا انصاف ہو، دنیا پر اعلی حکمرانی کی۔ لیکن جب مصطفی کمال نے ۱۹۲۴ء میں اقتدار سنبھال لیا اور ترکی کو لامذہب مملکت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا تو اس شاندار حکومت کاخاتمہ ہو گیا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ چاہئے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ اسلامی ریاست میں ہمارے آباؤ اجداد کس طریقے سے تہذیب وتمدن کی اعلی بلندی پر پہنچے تھے اور پھر ساری انسانیت کی رہنمائی کرنے لگے تھے اور آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ۲۳ سال کے مختصر عرصہ میں اسلامی نظام نے قبل از اسلام کے جاہل عرب معاشرہ کو دنیا کے سب سے جدید اور پر شکوہ معاشرے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسلام کی بنیا د اللہ تعالی پر ایمان لانے پر ہے جو کائنات کا خالق ہے اور جس نے قرآن کو اپنے پیغمبر محمد ﷺ کے ذریعہ بھیجا۔ خدا کا نظریہ یا دین جو اس بنیاد سے نکلتا ہے اس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر رکھا ہے جس نے انسان کے تعلق کو خالق سے جوڑا حتی کہ انسان کا اپنے آپ سے بھی تعلق جوڑا اور پھر اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق جوڑا مثلا تنازعات، کاروبار اور جنگ وغیرہ۔ خدا کے اس نظریے کا نفاذ پوری شکل میں ایسے ہوا تھا جسے ہم نظام خلافت کے نام سے جانتے ہیں۔
کسی بھی عمل کو پرکھنے کامعیار یہ ہے کہ اس کا حوالہ اور ماخذ قرآن ہو، سنت نبوی ہو، قیاس ہو اور اجماع صحابہؓ ہو۔ عمل کو پرکھنے کامعیار یہ ہے کہ اس کے کرنے میں خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو وہ حق ہے اور اگر غضب کا باعث ہے تو پھر وہ عمل باطل ہے۔ اس طرح اسلام نے راز فاش کر دیا اور عقلی طور پر جواب دے دیا کہ سب سے زیادہ دلچسپ سوال کیا ہیں؟ مثلا میں کہاں سے آیا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور میں کہاں جا رہا ہوں؟
ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ انسان کو خدا نے تخلیق کیا ہے اور انسان محدود ہے، اس کا علم محدود ہے خاص کر اپنے ارد گرد کے ماحول سے۔ لہذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ زندگی کا ایسا نظام بنائے جو اس کی خواہشات اور فطرت سے ہم آہنگ ہو۔ مثال کے طور پر یہ تو صرف رولس رائس کار کو بنانے والا ہی جان سکتا ہے کہ اس کی کار میں کیا کیا ہدایات موجود ہیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ کارکردگی دکھائی جا سکے۔ اسی طرح انسان ہے، اسے بھی اپنے بنانے والے کی ہدایات پر چلنا پڑتا ہے ، تب ہی اس کی زندگی کے اعمال طے کریں گے کہ اس عارضی زندگی میں اللہ کی ہدایات کا کتنا اتباع کیا ہے اور اسی حساب سے انسان کے لیے سزا یاجزا ہے۔
اسلام کے موثر نظام نے مسلمانوں کو انسانی کاوشوں کے تمام پہلوؤں میں ذہنی اعتبار سے اعلی بنا دیا ہے اور یہ ترقی خاص طور پر فوج میں نمایاں نظر آتی تھی کہ جس میں مسلم افواج کفار کے مقابلے میں ناقابل تسخیر ہونے کی شہرت رکھتے تھے۔ حتی کہ مسلمانوں کی تھوڑی سے تعداد بھی ہمیشہ وسیع کافر افواج پر غالب آجاتی تھی اور انہیں شکست دے دیتی تھی۔ اسلامی ریاست کی شاندار تاریخ اس حقیقت کی غماز ہے اوراس میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کے دور میں مسلمان مصر پر قابض ہو گئے اور پھر سپین پر طارق بن زیادکا قبضہ اور وہ بھی چند ہزا ر سپاہیوں کے ساتھ۔ یہ تو اسلام کی بے شمار فتوحات میں سے صرف دو مثالیں تھیں۔ ماضی کے ان مسلمانوں کا بڑا مقام تھا کیونکہ وہ اپنے خالق کے مکمل نظام کا اتباع کرتے تھے۔ ہم آج کے مسلمان بڑا نیچا مقام رکھتے ہیں کیونکہ ہم ایک نامکمل نظام کی پیروی کرتے ہیں جو انسانی دماغوں کی اختراع ہے، مثلا جمہوریت، اشتراکیت وغیرہ۔ مومن وہ ہے جو مکمل طور پر اسلام کی پیروی کرتا ہے اور اللہ ہمیشہ اسے فتح سے نوازتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ربانی ہے : ’’اللہ مومنوں کو منع فرماتا ہے اس بات سے کہ وہ کافروں کو اپنے اوپر غالب کر لیں‘‘ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست اور باوقار اسلامی ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقریبا پچاس غیر موثر ریاستوں میں بٹ گئی ہے۔ اور یہ تما م تر ریاستیں کفار کے خاص مفادات کا حصہ بن گئی ہیں۔ ان ٹوٹی ہوئی مسلم ریاستوں کے وسائل کفار ہی اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ استعمال کر رہے ہیں جن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ کسی طرح اسلام کو دوبارہ ایک سیاسی قوت بن کر دنیا پر چھا جانے سے روکیں اور کفار ہمارے وسائل کو آہستہ آہستہ زبردست لوٹ مار کا نشانہ بنائیں اور جو تھوڑا بہت بچ جائے وہ بھی انہی کی جیبوں میں ہم خود بھریں تاکہ شہریوں کے لیے کچھ بھی نہ رہے اور ظاہر ہے کہ وسیع پیمانے پر مسلمان ممالک میں غربت اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن الحمد للہ ، اللہ ہمیں آہستہ آہستہ مگر یقیناًجگا رہا ہے کہ ہم یہ محسوس کر لیں کہ ہماری پوزیشن غیر محفوظ اور نشانے پر ہے۔ اسی طرح گھناؤنے جرائم کے ذریعے جو کٹھ پتلی حکومتیں بے گناہ مسلمانوں کے خلاف ڈھا رہی ہیں، اور کفار کی نسل کشی کی مہمیں جو مسلمانوں کے خلاف بوسنیا، کشمیر، فلسطین اور چیچنیا میں چلائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ مسلمان ممالک میں بٹھائی گئی کٹھ پتلی انتظامیہ کے تحت ہو رہا ہے جو ہمیشہ چند روایتی الفاظ سے اظہار رد عمل کرتے ہیں : ’’ہم پر لازم ہے کہ ہم بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں‘‘ اور پھر مکمل لاپروائی برتتے ہیں۔
ان خطرات کو محسوس کر لینے سے ایک امیدکی کرن نظر آجاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ شکر ہے کہ اب مسلمانوں میں ان مسئلوں کا شعور پیدا ہو گیا ہے۔ اگر یہ مسئلہ مکمل طور پر اجاگر ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ انہیں کمزور بنا دینے کا نظام ان پر تھوپ دیا گیا ہے۔ اور ایسا کفار نے اپنی کٹھ پتلی حکومتوں کی مدد سے کیا ہے لیکن اس زوال کا علاج یہ ہے کہ ہم خالق کے کامل نظام کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ شرط ہے کہ اپنے دین کا مطالعہ کریں اور اسلام کے بھولے ہوئے حصے کو تلاش کر کے نافذ کریں جو کہ ابھی تک ہمارے اعمال سے خارج ہے۔ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے ڈھانچہ کو اور اس سے متعلقہ امور جو کہ اسلام سے اخذ کردہ ہوں اور ان کا کام ریاست کو چلانا ہو، ان کو سمجھے۔ الحمد للہ، سچے مسلمانوں کے گروہ ان موضوعات کا مطالعہ گہرائیوں تک کر چکے ہیں۔ اب ہم مسلمان لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کریں تاکہ اسلام اور اس کے نظام حکومت پر ان کا یقین مضبوط ہو اور وہ انہیں اس خلیفہ کی ریاست کے لیے تیار کرے جو اب ان شاء اللہ قریب ہی ہے۔
نقد روایت کا درایتی معیار ۔ مسلم فکر کے تناظر میں
محمد عمار خان ناصر
خبر کی اہمیت
انسانی علم کے عام ذرائع میں خبر بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا دائرۂ کار وہ امور ہیں جن تک انسان کے حواس اور عقل کی رسائی نہیں ہے۔ ہم اپنے حواس کی مدد سے صرف ان چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوں اور ہم ان پر دیکھنے، سننے، چھونے، سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیتیں بروئے کار لا سکتے ہوں۔ اسی طرح ہماری عقل صرف ان معلومات کو ترتیب دے کر مختلف نتائج اخذ کر سکتی ہے جو ہمارے حواس اس تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن باقی امور کے علم کے لیے ہمیں دوسرے انسانوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو ہمیں ان تجربات کے بارے میں بتا سکیں جو انہیں حاصل ہوئے یا ان واقعات کی خبر دے سکیں جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔
انسانی تمدن کی تشکیل اور ارتقا میں خبر نہایت اہم کردار کرتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم ان افراد اور گروہوں کے بارے میں جانتے اور ان کے حوالے سے مختلف علمی وعملی رویے اختیار کرتے ہیں جن سے ہمارا براہ راست واسطہ نہیں یا جو زمانی لحاظ سے ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور اسی کے ذریعے سے نسل انسانی مختلف میدانوں میں اپنے تجربات واکتشافات کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتی ہے۔
تاہم انسان کو حاصل ہونے والی دوسری تمام صلاحیتوں کی طرح، خبر کی صلاحیت بھی نقائص اور خامیوں سے پاک نہیں۔ خبر کی افادیت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس میں حقیقت واقعہ کو بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہو جیسی کہ وہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر خبر اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر کو روایت کرنے والے،جیسا کہ واضح ہے، انسانوں میں سے ہی کچھ افراد ہوتے ہیں اور اس کے مضمون کی ترتیب میں ان کی طبعی صلاحیتوں، مشاہدہ واستنباط کے طریقوں، ان کے گرد وپیش کے حالات اور ان کے کردار کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ تمام عوامل بالعموم واقعہ کی حقیقی تصویر کو خراب کرنے اور اس میں سے حقیقت کے عنصر کو کمزور کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
نقد خبر کا معیار
اس نقص کے ازالہ کے لیے نسل انسانی کے عقلا نے صدیوں کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں روایت کی جانچ پرکھ کے مختلف اصول وضع کیے ہیں جن کا اطلاق کر کے کسی بھی روایت کی تصدیق یا تکذیب کی جا سکتی اور ماخذ علم کے طور پر اس کا مقام متعین کیاجا سکتا ہے۔ یہ اصول وضوابط کیا ہیں؟ مولانا سید ابو الاعلی مودودیؒ کے حسب ذیل اقتباس میں نقد روایت کے بنیادی پہلو بیان کیے گئے ہیں:
’’ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کسی خبر کی تحقیق کا سخت سے سخت قابل عمل معیار کیا ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے زید نام کا ایک شخص اب سے سو برس پہلے گزرا ہے جس کے متعلق عمرو ایک روایت آپ تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ زید کے متعلق یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ اس غرض کے لیے آپ حسب ذیل تنقیحات قائم کر سکتے ہیں :
(۱) یہ روایت عمرو تک کس طریقے سے پہنچی؟ درمیان میں جو واسطے ہیں، ان کا سلسلہ زید تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ درمیانی راویوں سے ہر راوی نے جس شخص سے روایت کی ہے، اس سے وہ ملا بھی تھا یا نہیں۔ ہر راوی نے روایت کس عمر اور کس حالت میں سنی؟ روایت کو اس نے لفظ بلفظ نقل کیا یا اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کیا؟
(۲) کیا یہی روایت دوسرے طریقوں سے بھی منقول ہے؟ اگر منقول ہے تو سب بیانات متفق ہیں یا مختلف؟ اور اختلاف ہے تو کس حد تک؟ اگر کھلا ہوا اختلاف ہے تو مختلف طریقوں میں سے کون سا طریق زیادہ معتبر ہے؟
(۳) جن لوگوں کے واسطے سے یہ خبر پہنچی ہے، وہ خود کیسے ہیں؟ جھوٹے یا بد دیانت تو نہیں؟ اس روایت میں ان کی کوئی ذاتی یا جماعتی غرض تو مخفی نہیں؟ ان میں صحیح یاد رکھنے اور صحیح نقل کرنے کی قابلیتتھی یا نہیں؟
(۴) زید کی افتاد طبع، اس کی سیرت، اس کے خیالات اور اس کے ماحول کے متعلق جو مشہور ومتواتر روایات یا ثابت شدہ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ روایت ان کے خلاف تو نہیں ہے؟
(۵) روایت کسی غیر معمولی اور بعید از قیاس امر کے متعلق ہے یا معمولی اور قرین قیاس امر کے متعلق؟ اگر پہلی صورت ہے تو کیا طرق روایت اتنے کثیر، مسلسل اور معتبر ہیں کہ ایسے امر کو تسلیم کیا جا سکے؟ اور اگر دوسری صورت ہے تو کیا روایت اپنی موجودہ شکل میں اس امر کی صحت کا اطمینان کرنے کے لیے کافی ہے؟
یہی پانچ پہلو ہیں جن سے کسی خبر کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔‘‘ (۱)
اس اقتباس کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں روایت کی تنقید کے دو مستقل اور جداگانہ معیاروں کا ذکر کیا گیا ہے :
پہلا معیار ’’روایتی معیار‘‘ ہے جس میں اصل بحث راوی کی شخصیت، سند کے اتصال، روایت کے طریقوں اور اس کی مختلف سندوں سے ہوتی ہے۔ اقتباس میں مذکورپہلے تین امور اسی معیار سے متعلق ہیں۔
دوسرا معیار ’’درایتی معیار‘‘ ہے جس میں مذکورہ امورہ سے ہٹ کر دیگرعقلی قرائن کی روشنی میں روایت کے صحت واستناد کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اقتباس میں مذکور آخر ی دونوں امور اسی معیار کی وضاحت کرتے ہیں۔
درایت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم
درایت کا لغوی معنی جاننا ہے۔ المعجم الوسیط میں ہے: دری الشئی : علمہ بضرب من الحیلۃ ’’کسی چیز کی درایت کا مطلب ہے تگ ودو اور کوشش کر کے اس کو معلوم کرنا۔‘ ‘ (۲)
اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے ’’درایت‘‘ دو مختلف معنوں میں مستعمل ہے۔ پہلا مفہوم وہ ہے جو امام سیوطیؒ نے علامہ ابن الاکفانی ؒ سے نقل کیا ہے۔ ان کی تقسیم کے مطابق علم حدیث کی دو قسمیں ہیں : علم الروایہ اور علم الدرایہ۔ علم الروایہ کے تحت انہوں نے درج ذیل امور کا ذکر کیا ہے : نبی ﷺ کے اقوال وافعال، ان کی روایت، ان کا ضبط کرنا اور ان کے الفاظ کو تحریر میں لانا۔ جبکہ علم الدرایہ میں درج ذیل امور شامل ہیں : روایت کی حقیقت ، اس کی شرائط، انواع اور احکام، راویوں کے حالات اور ان کی شرائط، روایت کی مختلف اقسام اور ان سے متعلقہ امور۔ (۳)
دوسرے معنی کے لحاظ سے درایت کا لفظ ، مذکورہ بالا وسیع مفہوم کے بجائے، نقد روایت کے محدود تناظر میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد ایسے قرائن کا علم اور اطلاق ہوتاہے جن کا لحاظ رکھنا ، عقل عام اور روز مرہ انسانی تجربات ومشاہدات کی روشنی میں، کسی بھی خبر کا مقام متعین کرنے میں ضروری ہے۔
زیر نظر مقالہ میں ہمارا مقصود مسلمانوں کی علمی روایت میں نقد خبرکے درایتی معیار اور اس کے عملی اطلاق کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرنا ہے۔
درایتی نقد کے مختلف پہلو
سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیجئے کہ کسی روایت کو بلحاظ درایت پرکھتے ہوئے کون کون سے امور زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ مولانا مودودیؒ کے سابق الذکر اقتباس میں دو پہلو بیان کیے گئے ہیں :
۱۔ کسی شخص کے متعلق وارد روایت کے بارے میں یہ دیکھاجائے کہ وہ اس کی افتاد طبع، سیرت، خیالات اور اس کے ماحول کے متعلق ثابت شدہ معلومات کے خلاف تو نہیں ؟
۲۔ یہ دیکھا جائے کہ اگر روایت کسی غیر معمولی اور بعید از قیاس امر کے متعلق ہے تو کیا اس کے راوی اتنے زیادہ اور معتبر ہیں کہ محض ان کی شہادت پر ایسے امر کو تسلیم کیا جا سکے؟
سیرت النبی کے مقدمہ میں علامہ شبلیؒ نے جو بحث کی ہے، اس کی روشنی میں اس پر درج ذیل امور کااضافہ کیا جا سکتا ہے :
۳۔ رواۃ کے مختلف مدارج کو ملحوظ رکھا جائے۔ نہایت ضابط، نہایت معنی فہم اور نہایت دقیقہ رس راویوں کی روایات کو عام راویوں کی روایات پر ترجیح ہونی چاہئے۔ بالخصوص ان روایتوں میں یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہئے جو فقہی مسائل یا دقیق مطالب سے تعلق رکھتی ہیں۔
۴۔ یہ دیکھا جائے کہ راوی جو واقعہ بیان کرتا ہے، اس میں کس قدر حصہ اصل واقعہ ہے اور کس قدر راوی کا قیاس ہے۔ (۴)
مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ نے اس ضمن میں مزید چند امور کی نشان دہی کی ہے :
۶۔ واقعہ کے اصل راوی کے تعلقات صاحب واقعہ کے ساتھ کس قسم کے تھے؟
۷۔ نفس واقعہ کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ واقعہ اس ماحول میں پیش آ سکتا ہے؟
۸۔ اگر واقعہ کو صحیح مان لیا جائے تو طبعا جو نتائج اس پر مرتب ہونے چاہئیں، وہ ہوئے ہیں یا نہیں؟ (۵)
درایتی نقد کے یہ پہلوعام ہیں اور ان کا اطلاق ہر قسم کی روایات پر ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر زیر بحث روایت دینی لحاظ سے بھی اہمیت رکھنے والی ہویعنی اس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہو تو مزید دو پہلو پیش نظر رہنے چاہئیں جن کی تائید عقل عام سے بھی ہوتی ہے اور جن کی تصریح جلیل القدر محدثین اور فقہاء نے بھی کی ہے :
۹۔ روایت قرآن مجید کی نصوص یا رسول اللہ ﷺ کی سنت مشہورہ کے خلاف تو نہیں؟
۱۰۔ اس روایت کو تسلیم کرنے سے دین کے کسی مسلمہ اصول پر زد تو نہیں پڑتی؟
دین میں نقد درایت کی بنیاد
روایت کی تحقیق کرتے ہوئے حالات وقرائن کی روشنی میں اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کی تعلیم خود قرآن مجید نے دی ہے۔ سورۂ نور میں واقعہ افک کے ضمن میں ارشاد ہے :
لو لا اذ سمعتموہ ظن المومنون والمومنات بانفسھم خیرا وقالوا ھذا افک مبین
ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان کیا اور کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ (۶)
اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے بطلان کے قرائن اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ ان کو سنتے ہی ان کی تردید کر دینی چاہئے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے یہ بات سنی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا: ’’یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اے ام ایوب، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟‘‘ انہوں نے کہا :بخدا نہیں۔ تو فرمایا : ’’اللہ کی قسم، عائشہؓ تم سے بہتر ہیں‘‘ (۷)
مسند احمد میں حضرت ابو اسید الساعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
اذا سمعتم الحدیث تعرفہ قلوبکم وتلین لہ اشعارکم وابشارکم وترون انہ منکم قریب فانا اولاکم بہ واذا سمعتم الحدیث عنی تنکرہ قلوبکم وتنفر منہ اشعارکم وابشارکم وترون انہ منکم بعید فانا ابعدکم منہ
جب تم کوئی ایسی حدیث سنو جس سے تمہارے دل مانوس ہوں اور تمہارے بال وکھال اس سیمتاثر ہوں اور تم اس کو اپنے سے قریب سمجھوتو میں اس کا تم سے زیادہ حق دار ہوں اور جب کوئی ایسی حدیث سنو جس کو تمہارے دل قبول نہ کریں اور تمہارے بال وکھال اس سے متوحش ہوں اور تم اس کو اپنے سے دور سمجھو تو میں تم سے بڑھ کر اس سے دور ہوں ۔ (۸)
صحا بہ کرامؓ
درایت کی بنیاد پر روایت کو پرکھنے کے طریقے کا آغاز حضرات صحابہ کرامؓ ہی کے زمانے میں ہو چکا تھا اور جلیل القدر صحابہ کرامؓ کی آرا میں اس کے استعمال کے متعدد شواہد موجود ہیں :
حضرت عائشہؓ:
ام المومنین حضرت عائشہؓ کے ہاں قبول روایت کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور اصول شرع کے خلاف نہ ہو چنانچہ انہوں نے متعدد مواقع پر بعضصحابہ کرامؒ کی بیان کردہ روایتوں کو محض اس بنا پر رد کر دیا کہ وہ، ان کے نزدیک، اس معیار پر پورا نہیں اترتی تھیں۔ امام سیوطیؒ نے یہ روایات اپنے رسالہ عین الاصابہ فی ما استدرکتہ عائشۃ علی الصحابۃ میں درج کردی ہیں۔ (۹) یہاں ہم ان میں سے چند مثالیں نقل کرتے ہیں:
۱۔ حضرت ابن عمرؓ کی بیان کردہ یہ روایت جب حضرت عائشہؓ کے سامنے پیش کی گئی کہ ان المیت لیعذب ببکاء اھلہ علیہ (بے شک مرنے والے کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے) تو فرمایا : ’’ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات مومن کے بارے میں نہیں بلکہ کافر کے بارے میں فرمائی ہوگی۔ پھر فرمایا، تمہیں قرآن کافی ہے : لا تزر وازرۃ وزر اخری (کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی)
۲۔ حضرت عمرؓ نے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کی لاشوں سے، جو ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھیں، مخاطب ہو کر کہا : فھل وجدتم ما وعد ربکم حقا (تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کیا تمہیں اس کا حق ہونا معلوم ہو گیا ہے؟) صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا : ما انتم باسمع منھم ولکن لا یجیبون (ان کی سننے کی صلاحیت تم سے کم نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے) حضرت عائشہؓ نے یہ روایت سن کر کہا : آپ نے ایسا نہیں بلکہ یہ کہا ہوگا کہ اس وقت یہ لوگ جان چکے ہیں کہ جو میں ان سے کہتا تھا، وہ حق ہے۔ پھر آپؓ نے یہ آیات پڑھیں : انک لا تسمع الموتی (بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے) وما انت بمسمع من فی القبور (آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں)
۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے : الطیرۃ فی المراۃ والدابۃ والدار (نحوست عورت میں، سواری کے جانور میں اور گھر میں ہے) تو حضرت عائشہؓ نے کہا: اللہ کی قسم، رسول اللہ ﷺ ایسا نہیں کہتے تھے۔ آپ تو اہل جاہلیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ یوں کہتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی : ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھا۔ (تمہیں زمین میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ ایک کتا ب میں لکھی ہوئی یعنی طے شدہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں)
۴۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں داخل کر دیا کیونکہ وہ نہ اس کو خود کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ حضرت عائشہؓ نے یہ حدیث سن کر کہا : ’’اللہ کے ہاں مومن کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ اس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دے۔ یہ عورت ،درحقیقت، کافر تھی۔‘‘
۵۔ جب حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ روایت بیان کی کہ ’’جو آدمی وتر کی نماز نہ پڑھے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ‘‘ تو حضرت عائشہؓ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا : ’’رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی پانچ فرض نمازوں کی ، تمام شرائط کے ساتھ، پابندی کرے گا ، اللہ تعالی کے ہاں اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے۔‘‘
حضرت عمرؓ :
سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے یہ روایت بیان کی کہ ان کے خاوند نے انہیں تین طلاقیں دے دی تھیں تو رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عدت کے دوران میں ان کا نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا : ما کنا لندع کتاب ربنا وسنۃ نبینا لقول امراۃ لا ندری احفظت ام لا۔ ’’ہم کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کو ایک عورت کی بات پر نہیں چھوڑ سکتے جس کو پتہ نہیں بات یاد بھی رہی یا نہیں‘‘ (۱۰)
حضرت ابن عباسؓ:
۱۔ جامع ترمذی میں ہے کہ ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبد اللہ ابن عباسؓ نے اس کو خلاف عقل ہونے کی بنا پر قبول نہ کیا اور فرمایا : ’’کیا ہم چکناہٹ سے وضو کریں؟ کیا ہم گرم پانی کے استعمال سے وضو کریں؟ ‘‘ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا : ’’جب تمہارے سامنے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کی جائے تو باتیں نہ بنایا کرو۔‘‘ (۱۱)
۲۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عمرو نے جابر بن زید سے پوچھا ، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ، حکم بن عمرو الغفاری تو یہی بات کہتے تھے لیکن عبد اللہ ابن عباسؓ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے : قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما (کہہ دو کہ مجھ پر جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں ان چار چیزوں یعنی مردار، خون، خنزیر کے گوشت یا غیر اللہ کے نام پر منت مانے ہوئے جانورکے سوا میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا) (۱۲)
حضرت ابو ایوب انصاریؓ:
صحیح بخاری میں ہے کہ محمود بن الربیع نے یہ حدیث بیان کی کہ : ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ (جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا) حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے یہ سنا تو فرمایا: واللہ ما اظن رسول اللہ ﷺ قال ما قلت قط (بخدا میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی ایسی بات فرمائی ہوگی)
حافظ ابن حجرؓ ان کے انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا ظاہرمفہوم یہ ہے کہ گناہ گار موحدین جہنم میں نہیں جائیں گے حالانکہ یہ بات بہت سی آیات اور مشہور احادیث کے خلاف ہے۔ (۱۳)
حضرت معاویہؓ:
موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت معاویہؓ نے سونے یا چاندی کے کچھ برتن فروخت کیے اور بدلے میں ان کے وزن سے زیادہ سونا یا چاندی وصول کی۔ جب حضرت ابو الدرداءؓ نے انہیں بتایا کہ اس بیع سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے تو جواب دیا : میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ (۱۴) گویا انہوں نے عقل وقیاس کی بنا پر روایت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔
محدثین کرام
محدثین نے جہاں روایت کی سند کی تحقیق کے سلسلے میں گراں قدر اصول وضع کیے ہیں، وہاں روایت کے متن کی تنقید کے سلسلے میں درایت کی اہمیت بھی تسلیم کی ہے۔ چنانچہ محدث عمر بن بدر الموصلی لکھتے ہیں:
لم یقف العلماء عند نقد الحدیث من حیث سندہ بل تعدوا الی النظر فی متنہ فقضوا علی کثیر من الاحادیث بالوضع وان کان سندا سالما اذا وجدوا فی متونھا عللا تقضی بعدم قبولھا
علما نے نقد حدیث کے معاملہ میں صرف سند پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس دائرے میں متن کو بھی شامل کیا ہے چنانچہ انہوں نے بہت سی ایسی حدیثوں کے موضوع ہونے کا فیصلہ کیا ہیجن کی سندیں اگرچہ درست تھیں لیکن ان کے متن میں ایسی خرابیاں پائی جاتی تھیں جو ان کو قبول کرنے سے مانع تھیں (۱۵)
درایت کے اصولو ں کی وضاحت کرتے ہوئے خطیب بغدادیؒ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں لکھتے ہیں:
واذا روی الثقۃ المامون خبرا متصل الاسناد رد بامور: احدھا ان یخالف موجبات العقول فیعلم بطلانہ لان الشرع انما یرد بمجوزات العقول واما بخلاف العقول فلا۔ والثانی ان یخالف نص الکتاب او السنۃ المتواترۃ فیعلم انہ لا اصل لہ اومنسوخ۔ والثالث ان یخالف الاجماع فیستدل علی انہ منسوخ او لا اصل لہ لانہ لا یجوز ان یکون صحیحا غیر منسوخ وتجمع الامۃ علی خلافہ۔ ۔۔۔۔۔ والرابع ان ینفرد الواحد بروایۃ ما یجب علی کافۃ الخلق علمہ فیدل ذلک علی انہ لا اصل لہ لانہ لا یجوز ان یکون لہ اصل وینفرد ہو بعلمہ من بین الخلق العظیم۔ والخامس ان ینفرد بروایۃ ما جرت العادۃ بان ینقلہ اھل التواتر فلا یقبل لانہ لا یجوز ان ینفرد فی مثل ھذا بالروایۃ
جب کوئی ثقہ اور مامون راوی ایسی روایت بیان کرے جس کی سند بھی متصل ہے تو اس کو ان امور کے پیش نظر رد کر دیا جائے گا : ایک یہ کہ وہ تقاضائے عقل کے خلاف ہو ۔ اس سے اس کا بطلان معلوم ہوگا کیونکہ شرع کا ورود عقل کے مقتضیات کے مطابق ہوتاہے نہ کہ عقل کے خلاف۔ دوسرے یہ کہ وہ کتاب اللہ کی نص یا سنت متواترہ کے خلاف ہو۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اس کی کوئی اصل نہیں یا یہ منسوخ ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ اجماع کے خلاف ہو۔ اس سے یہ استدلال کیا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے یا اس کی کوئی اصل نہیں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صحیح اور غیر منسوخ ہو اور امت کا اس کے خلاف اجماع ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ ایسے واقعہ کو صرف ایک راوی بیان کرے جس کا جاننا تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی کوئی اصل نہیں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی بات کی کوئی اصل ہو اور تمام لوگوں میں سے صرف ایک راوی اس کو نقل کرے۔ پانچویں یہ کہ ایسی بات کو صرف ایک آدمی نقل کرے جس کو عادتا لوگ تواتر کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ جائز نہیں کہ ایسے واقعہ کو نقل کرنے والا صرف ایک آدمی ہو (۱۶)
امام ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں:
ما احسن قول القائل : اذا رایت الحدیث یباین المعقول او یخالف المنقول او یناقض الاصول فاعلم انہ موضوع
کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک حدیث عقل کے خلاف ہے یا ثابت شدہ نص کے مناقض ہے یا کسی اصول سے ٹکراتی ہے تو جان لو کہ وہ موضوع ہے۔ (۱۷)
ذیل میں ہم وہ مثالیں پیش کرتے ہیں جن میں جلیل القدر محدثین نے ان اصولوں کو برتتے ہوئے درایتی معیار پر پورا نہ اترنے والی روایات کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اگرچہ ان کے راوی نہایت ثقہ اور اسانید بالکل متصل ہیں۔
۱۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ ایک جھگڑے کے سلسلے میں حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا:
اقض بینی وبین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن
میرے اور اس جھوٹے، گناہ گار، بد عہد اور خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے۔
امام نوویؒ ، علامہ مازریؒ سے نقل کرتے ہیں:
ھذا اللفظ الذی وقع لا یلیق ظاہرہ بالعباس وحاش لعلی ان یکون فیہ بعض ھذہ الاوصاف فضلا عن کلھا ولسنا نقطع بالعصمۃ الا للنبی ﷺ ولمن شھد لہ بہا لکنا مامورون بحسن الظن بالصحابۃ رضی اللہ عنھم اجمعین ونفی کل رذیلۃ عنھم واذا انسدت طرق تاویلھا نسبنا الکذب الی رواتھا
اس روایت میں واقع یہ الفاظ بظاہر حضرت عباس سے صادر نہیں ہو سکتے اور یہ ناممکن ہے کہ سیدنا علیؓ کی ذات میں ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہو۔ اور ہمارا رسول اللہ ﷺ اور ان لوگوں کے علاوہ جن کے بارے میں آپ نے شہادت دی، کسی کے بارے میں بھی معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ صحابہؓ کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور ہر بری بات کی ان سے نفی کریں۔ جب تاویل کے تمام راستے بند ہو جائیں تو پھر ہم جھوٹ کی نسبت روایت کے راویوں کی طرف کریں گے۔ (۱۸)
۲۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے کہ ان پر ذلت اور سیاہی چچھائی ہوئی ہے تو اللہ تعالی سے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ میں جنت کو کافروں پر حرام کر رکھا ہے۔
امام اسماعیلیؒ فرماتے ہیں:
ھذا خبر فی صحتہ نظر من جھۃ ان ابراھیم علم ان اللہ لا یخلف المیعاد فکیف یجعل ما صار لابیہ خزیا مع علمہ بذالک
س روایت کی صحت میں اشکال ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو ان کے والد کا جو انجام ہوا، اس کو وہ کیسے اپنی رسوائی قرار دے سکتے ہیں؟ (۱۹)
۳۔ صحیح بخاری میں عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر کو دیکھا جس نے زنا کیا تھا۔ اس پر دوسرے بندروں نے جمع ہو کر اس کو سنگ سار کیا۔
حافظ ابن عبد البرؒ اس حدیث پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
فیھا اضافۃ الزنا الی غیرمکلف واقامۃ الحد علی البھائم وھذا منکر عند اھل العلم
اس میں زنا کی نسبت غیر مکلف کی طرف کی گئی ہے اور جانوروں پر حد لگانے کا ذکر ہے ۔ اہل علم کے نزدیک یہ بات بعید از قیاس ہے۔ (۲۰)
۴۔ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عبد اللہ بن ابی کے حامیوں اور آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ کے مابین جھگڑا ہو گیا جس پر یہ آیت اتری: وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینھما
محدث ابن بطالؒ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں دو مومن گروہوں میں صلح کرانے کا ذکر ہے جبکہ روایات کے مطابق عبد اللہ بن ابی اور اس کا گروہ اس وقت تک علانیہ کافر تھا۔ (۲۱)
۵۔ سن ابی داؤد میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کرتے ہوئے اپنے اعضا کو تین تین مرتبہ دھویا اور پھر فرمایا : من زاد علی ھذا او نقص فقد اساء وظلم (جس نے اس تعداد میں کمی بیشی کی، اس نے برا کیا اور ظلم کیا)
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں :
اسنادہ جید لکن عدہ مسلم فی جملۃ ما انکر علی عمرو بن شعیب لان ظاھرہ ذم النقص من الثلاث
اس کی سند عمدہ ہے لیکن امام مسلم نے اس کو عمرو بن شعیب کے منکرات میں شمار کیا ہے کیونکہ ظاہرکے لحاظ سے یہ روایت تین مرتبہ سے کم دھونے والے کی مذمت کرتی ہے (حالانکہ صحیح روایات میں رسول اللہ ﷺ سے ایسا کرنا ثابت ہے) (۲۲)
۶۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے ہوا۔
امام ابن حزمؒ اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد ہوا تھا اس لیے روایت میں مذکور بات درست نہیں ہو سکتی۔ (۲۳)
۷۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیانؓ نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو اپنی دختر حضرت ام حبیبہؓ کے ساتھ نکاح کی پیش کش کی۔
ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حضرت ام حبیبہؓ کے ساتھ نکاح فتح مکہ سے بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا جبکہ ابو سفیانؓ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لہذا اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ (۲۴)
۸۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ موسی علیہ السلام کے کہنے پر نمازوں میں تخفیف کے لیے بار بار اللہ تعالی کے پاس جاتے رہے ۔ آخری مرتبہ جب آپ واپس آئے اور موسی علیہ السلام نے پھرواپس جانے کو کہا تو آپ نے انہیں اللہ تعالی کا ارشاد سنایا کہ : ما یبدل القول لدی (اس حکم میں مزید کوئی تبدیلی نہیں ہوگی) لیکن موسی علیہ السلام نے پھر بھی آپ سے دوبارہ جانے کے لیے کہا۔
محدث داؤدی فرماتے ہیں کہ یہ با ت درست نہیں کیونکہ باقی تمام روایات اس کے برخلاف بات بیان کرتی ہیں نیز موسی علیہ السلام، اللہ تعالی کا ارشاد سننے کے بعد آپ ﷺ کو دوبارہ جانے کا نہیں کہہ سکتے۔ (۲۵)
۹۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺنے اپنی قمیص اس کے بیٹے کو دی اور حکم دیا کہ اس میں اس کو کفن دیا جائے۔ پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھے تو حضرت عمرؓ نے کہا: کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ وہ منافق ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع بھی کیاہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں ستر مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ستر سے زیادہ مرتبہ دعا کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔
اس روایت کو متعدد محدثین نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں :
واستشکل فھم التخییر من الایۃ حتی اقدم جماعۃ من الاکابر علی الطعن فی صحۃ ھذا الحدیث مع کثرۃ طرقہ واتفاق الشیخین وسائر الذین خرجوا الصحیح علی تصحیحہ ۔۔۔۔۔ انکر القاضی ابوبکر صحۃ ھذا الحدیث وقال : لا یجوز ان یقبل ھذا ولا یصح ان الرسول قالہ انتھی۔ ولفظ القاضی ابی بکر الباقلانی فی التقریب : ھذا الحدیث من اخبار الاحاد التی لا یعلم ثبوتھا۔ وقال امام الحرمین فی مختصرہ : ھذا الحدیث غیر مخرج فی الصحیح۔ وقال فی البرھان : لا یصححہ اھل الحدیث۔ وقال الغزالی فی المستصفی : الاظھر ان ھذا الخبر غیر صحیح۔ وقال الداودی الشارح : ھذا الحدیث غیر محفوظ
رسول اللہ ﷺ کا آیت سے اختیار کا مفہوم اخذ کرنا محل اشکال سمجھا گیا ہے اسی لیے اکابر اہل علم کی ایک جماعت نے ، باوجودیکہ اس حدیث کی سندیں بہت سی ہیں اور شیخین اور صحیح احادیث جمع کرنے والے دوسرے محدثین اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں، اس حدیث کی صحت پر اعتراض کیا ہے۔ قاضی ابوبکر نے اس حدیث کو صحیح ماننے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو قبول کرنا جائز نہیں اور نہ رسول اللہ ﷺ ایسا فرما سکتے ہیں۔ تقریب میں قاضی ابوبکر الباقلانی کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ حدیث ان اخبار آحاد میں سے جن کا ثبوت مشکوک ہے۔ امام الحرمین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح احادیث کے زمرے میں نہیں ہے۔ برہان میں کہتے ہیں کہ اس کو علماء حدیث صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ غزالی مستصفی میں لکھتے ہیں کہ اس کا غیر صحیح ہونا بالکل واضح ہے۔ شارح داؤدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ (۲۶)
فقہاء حنفیہ
فقہاء حنفیہ کے ہاں روایت کے درایتی نقد کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے نہایت مضبوط اصول وضع کیے ہیں۔ امام سرخسیؒ ان اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
فاما القسم الاول وھو ثبوت الانقطاع بدلیل معارض فعلی اربعۃ اوجہ :اما ان یکون مخالفا لکتاب اللہ تعالی او السنۃ المشھورۃ عن رسول اللہ او یکون حدیثا شاذا لم یشتھر فی ما تعم بہ البلوی ویحتاج الخاص والعام الی معرفتہ او یکون حدیثا قد اعرض عنہ الائمۃ من الصدر الاول بان ظھر منھم الاختلاف فی تلک الحادثۃ ولم تجر بینھم المحاجۃ بذلک الحدیث
دوسری دلیل کے ساتھ تعارض کے اعتبار سے روایت کے منقطع ہونے کی چار صورتیں ہیں : یا تو روایت کتاب اللہ کے خلاف یا رسول اللہ ﷺ کی مشہور سنت کے خلاف ہو۔ یا عموم بلوی میں کوئی شاذ اور غیر مشہور حدیث وارد ہو جبکہ اس کی معرفت ہر خاص وعام کو ہونی چاہئے۔ یا کوئی ایسی حدیث ہو جس سے صدر اول کے ائمہ نے اعراض کیا ہو ۔ یعنی ان کے مابین اس مسئلے کے بارے میں بحث ہوئی ہو لیکن اس حدیث سے انہوں نے استدلال نہ کیا ہو۔ (۲۷)
ایک دوسری بحث میں لکھتے ہیں :
اذا انسد باب الرای فی ما روی وتحققت الضرورۃ بکونہ مخالفا للقیاس الصحیح فلا بد من ترکہ
جب کسی روایت کے ماننے سے رائے کا باب بالکل بند ہوتا ہو اور اور ہر پہلو سے واضح ہو جائے کہ وہ قیاس صحیح کے مخالف ہے تو اس کو چھوڑنا لازم ہے (۲۸)
فقہاء احناف نے ان اصولوں کی بنیا دپر جن روایتوں کو رد کیا ہے، وہ حسب ذیل ہیں:
مخالف قرآن روایات
۱۔ ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ’’جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے، اسے چاہئے کہ وہ وضو کر ے‘‘
سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں مسجد قبا کے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے : فیہ رجال یحبون ان یتطھروا (اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب طہارت حاصل کریں) یعنی پانی سے استنجا کریں۔ ظاہر ہے کہ پانی سے استنجا شرمگاہ کو ہاتھ لگائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اللہ تعالی نے اس عمل کو طہارت حاصل کرنے سے تعبیر کیا ہے جبکہ مذکورہ حدیث میں،اس کے برخلاف، مس ذکر کو نقض طہارت کو سبب قرار دیا گیا ہے ،اس لیے یہ حدیث قابل قبول نہیں ۔
(۲) فاطمہ بنت قیس رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ ایسی عورت کا نفقہ خاوند کے ذمہ واجب نہیں جس کو تین طلاقیں دی گئی ہوں۔
سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے : اسکنوھن من حیث سکنتم من وجدکم ’’تم انکو ٹھہراؤ جہاں تم خود ٹھہرے ہو، اپنی طاقت کے مطابق‘‘ آیت میں اسکنوھن سے مراد انفقوھن ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نفقہ خاوند کے ذمہ ہے، لہذا مذکورہ حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔
(۳) صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض مقدمات میں ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔
سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کتاب اللہ کے اس حکم کے منافی ہے: واستشھدوا شھیدین من رجالکم ’’اور تم گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو‘‘ اس لیے ناقابل قبول ہے۔
سنت مشہورہ کے خلاف روایت
(۱) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے تر کھجور کے عوض میں خشک کھجور کی بیع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا : کیا تر کھجور خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ سائل نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا : تو پھر یہ بیع جائز نہیں۔
سرخسی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؓ نے اس روایت پر عمل نہیں کیا کیونکہ یہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد میں ہے : التمر بالتمر مثل بمثل (کھجور کے بدلے میں کھجور لی جائے تو مقدار ایک جیسی ہونی چاہئے) اس حدیث میں ہم جنس اشیا کے باہمی مبادلہ کے لیے مطلق مماثلت کی (یعنی بوقت بیع) شرط لگائی گئی ہے، جبکہ سعدؓ کی مذکورہ روایت میں، اس کے برخلاف، یہ کہا گیا ہے کہ مماثلت اس حالت کے اعتبار سے ہونی چاہئے جبکہ تر کھجور خشک ہو جائے۔
عموم بلوی میں وارد خبر واحد
سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ اس اصول کی بنا پر ہمارے علما نے درج ذیل روایات کو قبول نہیں کیا
(۱) وہ روایات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
(۲) وہ روایات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنازہ کی چارپائی اٹھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
(۳) وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کی تلاوت کی۔
(۴) وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔
وہ روایات جن سے صحابہؓ نے استدلال نہیں کیا
سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ درج ذیل روایات سے صحابہؓ نے، باوجودیکہ ان مسائل کے متعلق ان کے مابین مباحثہ واستدلال ہوا، استدلال نہیں کیا، اس لیے قابل قبول نہیں :
(۱) الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء (طلاق مردوں کے اعتبار سے ہے اور عدت عورتوں کے اعتبار سے)
(۲) ابتغوا فی اموال الیتامی خیرا کی لا تاکلھا الصدقۃ (زیر پرورش یتیموں کے مال کو کاروبار میں لگاؤ ، ایسا نہ ہو کہ مسلسل زکاۃ دینے سے وہ ختم ہو جائیں) (۲۹)
قیاس کے خلاف روایات
اگر غیر فقیہ راوی ایسی روایت بیان کرے جو قیاس صحیح کے مخالف ہے، تو قیاس کو روایت پر ترجیح ہوگی۔ اس اصول پر حسب ذیل روایات سرخسیؒ کے ہاں ناقابل قبول قرار پاتی ہیں :
(۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : اگر کوئی شخص ایسا جانور خریدے جس کا دودھ گاہک کو دھوکا دینے کے لیے کئی دنوں سے نہیں دوہا گیا تھا، تو اگر وہ اس کو رکھنے پر راضی ہو تو درست، ورنہ جانور کو واپس کر دے اور استعمال شدہ دودھ کے بدلے میں ایک صاع کھجوریں دے۔
سرخسیؒ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہر لحاظ سے قیاس صحیح کے مخالف ہے کیونکہ استعمال شدہ دودھ کے تاوان کے طور پر یا تو اتنی ہی مقدار میں دودھ دینا چاہئے اور یا اس کی قیمت۔ ہر حالت میں ایک صاع کھجوروں کا تاوان دینے کی کوئی تک نہیں ہے۔
(۲) سلمہ بن المحبقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی لونڈی سے مباشرت کر لی تو اگر اس میں لونڈی کی رضامندی شامل تھی تو اب وہ لونڈی خاوند کی ملکیت میں آگئی اور اس کے عوض میں وہ یبوی کو اس جیسی کوئی اور لونڈی دے دے۔ اور اگر خاوند نے لونڈی کو مجبور کیا ہے تو اب وہ آزاد ہے اور اس کے عوض میں خاوند اپنی بیوی کو اس جیسی کوئی اور لونڈی دے۔
سرخسیؒ فرماتے ہیں کہ ازروئے قیاس یہ حدیث ناقابل فہم ہے، لہذا قابل قبول نہیں۔ (۳۰)
مسلمات کے خلاف روایات
۱۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ قرآن مجید میںیہ حکم نازل ہوا تھا کہ حرمت رضاعت تب ثابت ہوگی جب بچے نے دس مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیا ہو۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ یہ حکم نازل ہوا کہ پانچ مرتبہ دودھ پینے سے وہ عورت بچے کی ماں بن جائے گی۔ یہ آیت رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بھی قرآن مجید میں تلاوت کی جاتی تھی۔
امام ابوبکر الجصاصؒ اس پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
اما حدیث عائشۃ فغیر جائز اعتقاد صحتہ علی ما ورد ۔۔۔۔ ولیس احد من المسلمین یجیز نسخ القرآن بعد موت النبی ﷺ فلو کان ثابتا لوجب ان تکون التلاوۃ موجودۃ
اس حدیث کی صحت کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں کیونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد قرآن میں نسخ کو جائز نہیں مانتا تو اگر یہ روایت درست ہوتی تو یہ آیت قرآن میں موجود ہوتی۔ (۳۱)
اس روایت کے بارے میں یہی رائے امام سرخسیؒ نے بھی ظاہر کی ہے۔ (۳۲)
۲۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور کہا : کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو اس سے منع کیا ہے؟ لیکن رسول اللہ ﷺ نے پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔
امام طحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
لان محالا ان یکون اللہ تعالی ینھی نبیہ عن شئی ثم یفعل ذلک الشئی ولا نری ھذا الا وھما من بعض رواۃ الحدیث
یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو کسی کام سے منع کرے اور پھر نبی وہی کام کرے۔ ہمارے خیال میں یہ کسی راوی کا وہم ہے۔
اس کے بعد انہوں نے متعدد روایات سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ (۳۳)
۳۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ لبید بن اعصم یہودی نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا جس کا اثرآپ پر اس طرح ظاہر ہوا کہ آپ کام کرنے کے بعد بھول جاتے کہ آپ نے اسے کیا ہے۔
امام جصاصؒ اس روایت کی سخت الفاظ میں تردید کرتے ہیں:
ومثل ھذہ الاخبار من وضع الملحدین ۔۔۔۔۔ والعجب ممن یجمع بین تصدیق الانبیاء علیہم السلام واثبات معجزاتھم وبین التصدیق بمثل ھذا من فعل السحرۃ
اس طرح کی روایات ملحدین کی وضع کردہ ہیں۔ اور ان لوگوں پر تعجب ہے جو انبیا کی تصدیق کرتے اور ان کے معجزات کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ جادوگر انبیا پریہ عمل کر سکتے ہیں۔ (۳۴)
فقہاء مالکیہ
فقہاء مالکیہ کے ہاں بھی درایتی نقد کا استعمال نمایاں طور پر ملتا ہے۔ امام شاطبیؒ لکھتے ہیں:
ھذا القسم علی ضربین : احدھما ان تکون مخالفتہ للاصل قطعیۃ فلا بد من ردہ۔ والآخر ان تکون ظنیۃ اما بان یتطرق الظن من جھۃ الدلیل الظنی واما من جھۃ کون الاصل لم یتحقق کونہ قطعیا وفی ھذا الموضع مجال للمجتھدین ولکن الثابت فی الجملۃ ان مخالفۃ الظنی لاصل قطعی یسقط اعتبار الظنی علی الاطلاق وھو مما لا یختلف فیہ
ظنی دلیل اگر قطعی دلیل کے مخالف ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں : ایک یہ کہ اس کا اصل کے مخالف ہونا قطعی ہو ، اس صورت میں اس کو رد کرنا لازم ہے۔ دوسری یہ کہ ا س کا اصل کے خلاف ہونا ظنی ہو، یاتو اس لیے کہ اصل کے ساتھ اس کی مخالفتظنی ہے اور یا اس لیے کہ اصل کا قطعی ہونا متحقق نہیں ہوا۔ اس دوسری صورت میں مجتہدین کے لیے اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن اصولی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ ظنی کا قطعی کے مخالف ہونا ظنی کو ساقط الاعتبار کر دیتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (۳۵)
چنانچہ امام مالکؒ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ظاہر قرآن، عمل اہل مدینہ اور قیاس قوی کے معارض ہو تو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اس اصول پر انہوں نے متعدد روایات کو قبول نہیں کیا ۔
مخالف قرآن روایات
۱۔ حدیث : من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ (جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی ا سی طرف سے روزے رکھے) شاطبیؒ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
لمنافاتہ للاصل القرآنی الکلی نحو قولہ تعالی : الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی
کیونکہ یہ قرآن کے بیان کردہ اس ضابطہ کے خلاف ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور یہ کہ انسان کے لیے وہی عمل کارآمد ہیں جو اس نے خود کیے ہوں (۳۶)
۲۔ ایسی احادیث جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک بچہ پانچ یا دس مرتبہ کسی عورت کا دودھ نہ پی لے، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ شاطبی فرماتے ہیں :
ولم یعتبر فی الرضاع خمسا ولا عشرا للاصل القرآنی فی قولہ : وامھاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وفی مذھبہ من ھذا کثیر
امام مالک نے رضاع میں پانچ یا دس مرتبہ کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ قرآن کی اس آیت کے (عموم کے) خلاف ہے : وامہاتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ ۔ اور اس کی مثالیں ان کے مذہب میں بہت زیادہ ہیں۔ (۳۷)
مخالف عمل اہل مدینہ
ابن عبد البرؒ لکھتے ہیں :
فجملۃ مذھب مالک فی ذلک ایجاب العمل بمسندہ ومرسلہ ما لم یعترضہ العمل بظاہر بلدہ
امام مالک کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خبر واحد پر، چاہے وہ مسند یا ہو مرسل، عمل کرتے ہیں جب تک کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو۔ (۳۸)
اس اصول پر انہوں نے حسب ذیل روایات رد کی ہیں:
۱۔ خیار مجلس کی احادیث ۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں:
ولا یری العمل بحدیث خیار المتبایعین ۔۔۔۔ لما اعترضھما عندہ من العمل
امام مالکؒ خیار مجلس کی حدیث پر عمل نہیں کرتے کیونکہ یہ عمل اہل مدینہ کے معارض ہے۔ (۳۹)
۲۔ حضر کی حالت میں موزوں پر مسح کرنے کی روایات۔ ابو الولید ابن رشدؒ الجد لکھتے ہیں:
وسئل عن المسح علی الخفین فی الحضر ایمسح علیہما؟ فقال لا، ما افعل ذلک ۔۔۔۔ وانما ھی ھذہ الاحادیث ۔ قال : ولم یروا یفعلون ذلک وکتاب اللہ احق ان یتبع ویعمل بہ
امام مالکؒ سے حضر میں مسح علی الخفین کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، میں ایسا نہیں کرتا۔ اس کے حق میں تو بس یہ حدیثیں ہی ہیں۔ جبکہ خلفاء راشدین (اور اہل مدینہ) کا عمل اس پر نہیں ہے۔ (اس صورت میں) کتاب اللہ کے حکم (غسل) پرہی عمل کرنا درست ہے (۴۰)
مخالف قیاس
۱۔ وہ روایات جن میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو برتن کو سات مرتبہ دھویا جائے۔ شاطبیؒ امام مالکؒ سے نقل کرتے ہیں:
جاء الحدیث ولا ادری ما حقیقتہ؟ وکان یضعفہ ویقول : یؤکل صیدہ فکیف یکرہ لعابہ؟
حدیث تو آئی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کمزوری بتاتے ہوئے امام مالکؒ فرماتے تھے کہ اگر کتے کا شکار کیا ہوا جانور کھایا جا سکتا ہے تو اس کا لعاب کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ (۴۱)
۲۔ سات آدمیوں کی طرف سے ایک گائے یا اونٹ کی قربانی کی روایات۔ چونکہ قیاس یہ ہے کہ ہر آدمی کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا جائے، اس لیے امام مالکؒ ان روایات پر عمل نہیں کرتے۔ ابن رشد الحفیدؒ لکھتے ہیں۔
رد الحدیث لمکان مخالفتہ للاصل فی ذلک
اصل کی مخالفت کی وجہ سے امام مالکؒ نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے۔ (۴۲)
۳۔ وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ان ہانڈیوں کو الٹنے کا حکم دیا جن میں مال غنیمت کے اونٹوں اور بکریوں کا گوشت، غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہی پکایا جا رہا تھا۔ شاطبیؒ لکھتے ہیں:
تعویلا علی اصل رفع الحرج الذی یعبر عنہ بالمصالح المرسلۃ فاجاز اکل الطعام قبل القسم لمن احتاج الیہ
ان روایتوں کو امام مالکؒ نے رفع حرج یعنی مصالح مرسلہ کے اصول کے منافی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ اس لیے وہ ضرورت مند کے لیے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل بھی اس میں سے کھانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ (۴۳)
اس تمام تفصیل سے واضح ہے کہ اسلام کی علمی روایت میں درایت ایک نہایت شاندار تاریخ رکھتی ہے۔ مختلف طریقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے علما، محدثین اور فقہا نے اپنے اپنے زوق کے مطابق روایتوں کو پرکھنے کے مختلف عقلی اصول وضع کیے اور ان کو اپنی تحقیقات میں برتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہم ان کی انفرادی تحقیقات سے اختلاف کریں اور کسی معقول تاویل سے یہ واضح کردیں کہ زیر بحث روایت، درحقیقت، خلاف اصول نہیں ہے لیکن ، اہل علم کی مجموعی تحقیقات کی روشنی میں یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ درایت کی روشنی میں روایات کو پرکھنا ایک مسلمہ علمی اصول ہے اور جب کسی روایت کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ قرآن کی کسی نص، رسول اللہ ﷺ کی سنت ثابتہ، دین کے مسلمات یا عقل عام کے تقاضوں کے خلاف ہے تو اس کو یکسر رد کر دینا چاہئے، چاہے اس کی سند کتنی ہی صحیح اور اس کے طرق کتنے ہی کثیر ہوں۔ واللہ اعلم
حوالہ جات
(۱) مودودی، ابو الاعلی، سید : تفہیمات، لاہور : اسلامک پبلی کیشنز، ۲۰۰۰ء، حصہ اول، ص ۳۴۵
(۲) المعجم الوسیط، ایران : دفتر نشر فرہنگ اسلامی، ۱۴۰۸ھ، ص ۲۸۲
(۳) السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر: تدریب الراوی، ج ۱، ص ۴۰
(۴) شبلی نعمانی :سیرت النبی، لاہور : مکتبہ تعمیر انسانیت، ۱۹۷۵ء، ج ۱، ص ۱۰۱
(۵) سعید احمد اکبر آبادی : صدیق اکبرؓ،
(۶) سورۃ النور ، آیت ۱۶
(۷) ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل: تفسیر القرآن العظیم، لاہور : امجد اکیڈیمی، ۱۹۸۲ء، ج ۳، ص ۲۷۳
(۸) الامام احمد: المسند ، گوجرانوالہ: ادارہ احیاء السنۃ، سن ندارد، ج ۴، ص ۵
(۹) عین الاصابہ فی ما استدرکتہ عائشۃ علی الصحابہ، مشمولہ سیرت عائشہ: سید سلیمان ندوی، لاہور : اسلامی کتب خانہ، سن ندارد، ص ۲۶۶ تا ۲۸۱
(۱۰) ابو داؤد، سلیمان بن اشعث السجستانی: سنن ابی داؤد، المملکۃ العربیۃ السعودیۃ : دار السلام، ۲۰۰۰ء، کتاب الطلاق، باب فی نفقۃ المبتوتۃ، حدیث نمبر ۲۲۹۱
(۱۱) الترمذی، ابو عیسی محمد بن عیسی : جامع الترمذی، المملکۃ العربیۃ السعودیۃ : دار السلام، ۲۰۰۰ء، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء مما غیرت النار، حدیث نمبر ۷۹
(۱۲) البخاری، محمد بن اسماعیل : الجامع الصحیح مع شرحہ فتح الباری، دمشق : مکتبۃ الغزالی ، سن ندارد، حدیث نمبر ۵۵۲۹، ج ۹، ص ۶۵۴
(۱۳) ابن حجر، احمد بن علی العسقلانی : فتح الباری، دمشق : مکتبۃ الغزالی، سن ندارد، ج ۳، ص ۲۶
(۱۴) الامام مالک : الموطا، کراچی : میر محمد کتب خانہ، سن ندارد، باب بیع الذھب بالورق عینا وتبرا ، ص ۶۸۲
(۱۵) تقی امینی : حدیث کا درایتی معیار،کراچی :قدیمی کتب خانہ، ۱۹۸۶ء، ص ۱۷۹، ۱۸۰
(۱۶) الخطیب، ابوبکر احمد بن علی البغدادی : الفقیہ والمتفقہ، بیروت : دار الکتب العلمیہ، ۱۹۸۰، ج ۱، ص ۱۳۲، ۱۳۳
(۱۷) تدریب الراوی، ج ۱ ، ص ۲۷۷
(۱۸) النووی، ابو زکریا یحی بن شرف : شرح صحیح مسلم، دمشق : مکتبۃ الغزالی، سن ندارد، ج ۱۲، ص ۷۲
(۱۹) فتح الباری : ج ۸، ص ۵۰۰
(۲۰) فتح الباری : ج ۷، ص ۱۶۰
(۲۱) فتح الباری : ج ۵، ص ۲۹۹
(۲۲) فتح الباری : ج ۱، ص ۲۳۳
(۲۳) الامیر الیمانی، محمد بن اسماعیل : توضیح الافکار، بیروت : دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۶ھ، ج ۱، ص ۱۲۸، ۱۲۹
(۲۴) المرجع السابق
(۲۵) فتح الباری : ج ۱۳، ص ۴۸۶
(۲۶) فتح الباری، ج ۸، ص ۳۳۸
(۲۷) السرخسی، ابوبکر محمد بن احمد : اصول السرخسی، لاہور : دار المعارف النعمانیہ، ۱۹۸۱ء، ج ۱، ص ۳۶۴
(۲۸) اصول السرخسی : ج ۱، ص ۳۴۱
(۲۹) اصول السرخسی، ج ۱، ص ۳۶۴ تا ۳۷۰
(۳۰) اصول السرخسی : ج ۱، ص ۳۴۱
(۳۱) الجصاص، ابوبکر احمد بن علی الرازی، احکام القرآن، لاہور : سہیل اکیڈیمی، ۱۹۸۰، ج ۳، ص ۱۲۵
(۳۲) اصول السرخسی : ج ۲، ص ۷۹، ۸۰۔
(۳۳) الطحاوی، ابو جعفر احمد بن محمد : مشکل الآثار
(۳۴) احکام القرآن : ج ۱، ص ۴۶
(۳۵) الموافقات : ج ۳، ص ۱۸
(۳۶) الموافقات : ج ۳، ص ۲۲
(۳۷) الموافقات : ج ۳، ص ۲۳
(۳۸) ابن عبد البر: التمہید ، لاہور : المکتبۃ القدوسیۃ، ۱۹۸۳ء، :ج ۱، ص ۳
(۳۹) المرجع السابق
(۴۰) ابن رشد، ابو الولید القرطبی : البیان والتحصیل، بیروت : دار الغرب الاسلامی ، ۱۹۸۸ء، ج ۱، ص ۸۲
(۴۱) الموافقات : ج ۳، ص ۲۱
(۴۲) بدایۃ المجتہد: ج ۱، ص ۳۱۸
(۴۳) الموافقات : ج ۳، ص ۲۲
طالبان کے خلاف سلامتی کونسل کی قرارداد کا متن
ادارہ
اسلام آباد (نیوز ڈیسک) افغانستان پر پابندیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قرارداد کا متن درج ذیل ہے:
اقوام متحدہ کے منشور کے باب ہفتم پر عمل کرتے ہوئے :
۱۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ طالبان قرارداد نمبر ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کی تعمیل کریں جو بالخصوص بین الاقوامی دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں کو پناہ دینے اور تربیت دینے سے روکتی ہے ۔ اس قرارداد کے تحت طالبان اس بات کو یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات کریں کہ ان کے زیر کنٹرول علاقے کو دہشت گردی کی تنصیبات اور کیمپوں کے لیے یا دوسرے ملکوں یا ان کے شہریوں کے دہشت گردوں کی کارروائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ طالبان مقدمات میں ماخوذ بین الاقوامی دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی بین الاقوامی کوششوں میں تعاون کریں۔
۲۔ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ طالبان بلاتاخیر قرارداد نمبر ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کے پیراگراف نمبر کی پابندی کریں جو انہیں پابند کرتی ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو اس ملک کے حکام کے حوالے کریں جہاں وہ مقدمے میں ماخوذ ہیں یا ایسے ملک کے حکام کے حوالے کریں جہاں سے اسامہ کو ایسے ملک میں پہنچایا جا سکے یا ایسے ملک کے حکام کے حوالے کریں جہاں انہیں گرفتار کر کے موثر طو رپر مقدمہ چلایا جا سکے۔
۳۔ مزید مطالبہ کیا جاتا ہے کہ طالبان اپنے زیر کنٹرو ل علاقے میں دہشت گردوں کو تربیت دینے والے کیمپوں کو بند کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کیمپوں کو بند کرنے کی تصدیق اقوام متحدہ سے کرائی جائے۔ یہ تصدیق اقوام متحدہ کو ذیل کے پیراگراف ۱۹ کے تحت رکن ممالک سے حاصل ہونے والی معلومات اور ایسے دیگر ذرائع سے کی جائے جو اس قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔
۴۔ تمام رکن ممالک کو ان کی اس ذمہ داری سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ قرارداد نمبر ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کے پیراگراف ۴ کے تحت اقدامات کو یقینی بنائیں۔
۵۔ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تما م ممالک:
(اے) قرارداد نمبر ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کے تحت قائم کردہ کمیٹی (جسے آئندہ ’’کمیٹی‘‘ کہا جائے گا) کے نشان زدہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں بشمول اپنے شہریوں، وفاقوں، اپنے جھنڈے والی گاڑیوں، طیاروں کے ذریعے ہتھیاروں اور ہر قسم کی متعلقہ اشیاء بشمول اسلحہ، گولہ بارود، فوجی گاڑیوں، فوجی آلات، پیرا ملٹری سامان اور ان کے سپیئر پارٹس کی براہ راست یا بالواسطہ فراہمی، فروخت ، منتقلی کو روکیں گے۔
(بی) کمیٹی طالبان کے جن علاقوں کی نشاندہی کرے گی ان میں اپنے شہریوں، اپنے علاقوں سے طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں کے مسلح افراد کی فوجی سرگرمیوں سے متعلق معاملات میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر فنی مشوروں، معاونت یا تربیت فراہم، منتقل یا فروخت کرنے سے روکیں گے۔
(سی ) طالبان کو ملٹری یا متعلقہ سیکورٹی معاملات میں مشورہ دینے کے لیے افغانستان میں کنٹریکٹ یا کسی دوسرے انتظام کے تحت موجود اپنے افسران، ایجنٹوں، مشیروں اور فوجیوں کو واپس بلالیں گے اور اس معاملے سے متعلق دوسرے ملکوں کے شہریوں سے بھی ملک سے چلے جانے کے لیے کہیں گے۔
۶۔ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پیراگراف ۵ کے تحت عائد اقدامات کا اطلاق ا س غیر مہلک فوجی سامان پر مبنی امداد یا تربیت پر نہیں ہوگا جس کا مقصد صرف انسانیت کی بھلائی اور حفاظت ہوگا اور جس کے لیے کمیٹی پیشگی طو پر منظوری دے چکی ہوگی اور اس بات کی توثیق کی جاتی ہے کہ پیراگراف نمبر ۵ کے تحت عائد پابندیوں کا اطلاق اقوام متحدہ کے اہلکاروں، میڈیا کے نمائندوں اور انسانی بنیاد پر کام کرنے والے رضا کاروں کی جانب سے صرف ذاتی استعمال کے لیے افغانستان کو بھیجے جانے والے حفاظتی کپڑوں، بشمول فلیگ جیکٹوں اور فوجی ہیلمٹوں پر نہیں ہوتا۔
۷۔ تمام ممالک نے طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھنے پر زور دیا تاکہ طالبان مشنوں میں عملے کی تعداد اور سطح اور عہدوں کو کم سے کم حد تک رکھا جائے اور عملے کے جو ارکان باقی رہ جائیں ان کی اپنے علاقے میں نقل وحرکت کو کنٹرول یا پابند کیا جائے۔ بین الاقوامی تنظیموں میں طالبان مشنوں کے سلسلے میں میزبان ملک اگر ضروری سمجھتے ہوں تو ا س پیراگراف پر عملدرآمد کے لیے متعلقہ تنظیموں سے مشورہ کریں۔
۸۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام ممالک مزید اقدامات کریں گے:
(اے) اپنے ممالک میں طالبان کے تمام دفاتر مکمل اور فوری طور پر بند کر دیں گے۔
(بی) اپنے ممالک میں آریانہ افغان ایئر لائنز کے تمام دفاتر فوری طور پر بند کر دیں گے۔
(سی ) اسامہ بن لادن اور ان سے متعلق افراد اور ان کے فنڈز اور دیگر مالیاتی اثاثے بلاتاخیر منجمد کر دیں گے جن کا تعین کمیٹی نے کیا ہے۔ ان میں القاعدہ تنظیم اور اس کے فنڈز جو اسامہ بن لادن یا ان سے متعلق افراد کی ملکیت یا زیر کنٹرول سے بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل ہوتے ہیں اور اسامہ یا ان سے متعلق ادارے بشمول القاعدہ تنظیم شامل ہیں۔ کمیٹی سے درخواست کی گئی کہ وہ رکن ممالک اور علاقائی تنظیموں کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر ایسے افراد اور اداروں کی جن کا تعین اسامہ بن لادن کے ساتھیوں کی حیثیت سے کیا گیا ہے اور جو القاعدہ تنظیم میں ہیں، ایک تازہ ترین فہرست تیار کرے۔
۹۔ یہ مطالبہ کیا گیا کہ طالبان افیون اور دیگر غیر قانونی منشیات کی تمام سرگرمیاں بند کر دیں اور افیون کی غیر قانونی کاشت کے حقیقی خاتمے کے لیے کام کریں جن کی رقم دہشت گرد سرگرمیوں میں استعمال ہوتی ہے۔
۱۰۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام ممالک اپنے شہریوں اور اپنے علاقوں سے افغانستان کے زیر کنٹرول علاقے میں کسی بھی شخص کو جس کا تعین کمیٹی نے کیا ہے، کیمیکل ایسیٹیک اینہائیڈ رائیڈ کی فراہمی، منتقلی اور فروخت کی روک تھام کریں گے۔
۱۱۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام ممالک کسی بھی طیارے کو کمیٹی کے تعین کردہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقے کے لیے پرواز کرنے، اپنی علاقائی حدود پر سے گزرنے یا وہاں سے آنے والے طیارے کو اپنے ملک میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک ایسی کسی مخصوص پرواز کے لیے کمیٹی نے انسانی ضرورت کی بنیاد پر منظوری نہ دے دی ہو۔ ان میں مذہبی فرائض مثلا ادائیگی حج یا ایسی وجوہ کے لیے چلنے والی پروازیں جو تنازع افغانستان کے پرامن حل کو تقویت دیتی ہوں یا طالبان کی جانب سے اس قرارداد یا قرارداد ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کی تعمیل میں مدد دیتی ہوں، شامل ہیں۔
۱۲۔ کمیٹی افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے والی تنظیموں اور سرکاری ریلیف ایجنسیوں کی فہرست رکھے گی۔ ان میں اقوام متحدہ اور ا س کی ایجنسیاں اور بین الاقوامی ریڈ کراس وغیرہ شامل ہوں گی۔ پیراگراف ۱۱ کے ذریعے سے لگائی گئی پابندیوں کا طلاق متذکرہ بالا فہرست میں شامل تنظیموں اور سرکاری ریلیف ایجنسیوں کی طرف سے یا ان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازوں پر نہیں ہوگا۔ کمیٹی فہرست پر باقاعدگی سے نظر ثانی کرتی رہے گی۔ جن نئی تنظیموں اور ریلیف ایجنسیوں کا نام شامل کرنا مناسب ہوگا وہ شامل کرے گی اور ان کے نام خارج کر دے گی جن کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ انسانی مقاصد کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے پروازیں چلا رہی ہیں یا چلا سکتی ہیں۔ ان تنظیموں اور سرکاری ایجنسیوں کو فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا کہ ان کی یا ان کی طرف سے پروازوں پر پیراگراف ۱۱ کا اطلاق ہوگا۔
۱۳۔ طالبان اس بات کو یقینی بنائیں کہ امدادی اداروں کے افراد اور امداد کی ان کے زیر کنٹرول علاقے میں ضرورت مند افراد تک رسائی محفوظ اور بلا رکاوٹ ہو۔ طالبان اقوام متحدہ اور اس سے ملحق انسانی امدادی تنظیموں کے ارکان کی حفاظت، سلامتی اور آزادانہ نقل وحرکت یقینی بنانے کی ضمانت دیں۔
۱۴۔ تمام ریاستوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان کے نائب وزیر اور اس سے اوپر کے عہدے داروں ، اس کے برابر عہدے کے مسلح افراد اور طالبان کے دوسرے سینئر مشیروں اور اہم شخصیات کو اپنے علاقے میں داخل ہونے یا وہاں سے گزر کر کہیں جانے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ ماسوائے اس کے کہ وہ انسانی ہمدردی کے کسی مقصد سے، حج جیسے مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے یا افغان تنازع کے پرامن تصفیے کی خاطر مذاکرات کے لیے یا قرارداد ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) پر عمل درآمد کے سلسلے میں کہیں جا رہے ہوں۔
۱۵۔ کمیٹی کے مشورے سے سیکرٹری جنرل سے درخواست کی جاتی ہے کہ
(اے) ماہرین کی ایک کمیٹی قائم کی جائے جو قرارداد کی منظوری کے ساٹھ دن کے اندر کونسل کو سفارشات پیش کرے کہ رکن ملکوں کی اپنے قومی ذرائع سے حاصل کردہ اور سیکرٹری جنرل کو فراہم کردہ معلومات کے علاوہ اور کس کس طرح پیراگرافس ۳ اور ۵ کے مطابق ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی اور دہشت گردی کے تربیتی کیمپوں کے بند کرنے کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔
(بی) متعلقہ رکن ملکوں سے رابطہ کر کے اس قرارداد اور قرارداد ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کے ذریعے لگائی گئی پابندیوں پر عمل کرائیں اور بات چیت کے نتائج سے کونسل کو مطلع کریں۔
(سی) موجودہ اقدامات پر عملدرآمد اور عملدرآمد میں مشکلات کے بارے میں رپورٹ دیں۔ انہیں مستحکم کرنے کے لیے سفارشات اور اس سلسلے میں رکاوٹ بننے والے طالبان کے اقدامات کا جائزہ پیش کریں۔
(ڈی) وہ اس قرارداد اور قراراداد ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کے تحت اقدامات سے پیدا ہونے والی انسانی سطح کی پیچیدگیوں کا جائزہ لیں اور اس قرارداد کی منظوری کے نوے دن کے اندر سفارشات پیش کریں اور اس کے بعد ان اقدامات کی مدت ختم ہونے سے ۳۰ دن پہلے تک باقاعدگی کے ساتھ جامع رپورٹس دیتے رہیں۔
۱۶۔ کمیٹی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ قرارداد ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) میں بیان کردہ ٹاسک کے علاوہ مندرجہ ذیل کام سنبھال کر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔
(اے) رکن ممالک اور علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر وہ طیاروں کے طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں داخل ہونے اور اترنے کے مقامات کی فہرست مرتب کرے، اسے اپ ڈیٹ کرتی رہے اور فہرست کے مشمولات سے رکن ممالک کو مطلع کرے۔
(بی) رکن ممالک اور علاقائی تنظیموں کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر پیراگراف ۸ (سی) کے مطابق ایسے افراد اور ہستیوں کی فہرست مرتب کرے اور اسے اپ ڈیٹ کرتی رہے جن کااسامہ بن لادن سے تعلق ہے۔
(سی ) پیراگرافس ۶ اور ۱۱ میں بیان کردہ استثنایات کے لیے درخواستوں پر غور کر کے ان پر فیصلہ کرے۔
(ڈی) اس قرارداد کی منظوری کے ایک ماہ کے اندر پیراگراف ۱۲ کے مطابق افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے والی منظور شدہ تنظیموں اور سرکاری امدادی ایجنسیوں کی فہرست تیار کرے اور اسے اپ ڈیٹ کرتی رہے۔
(ای) ان اقدامات پر عملدرآمد سے متعلق اطلاعات کو عام ذرائع ابلاغ اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے عام کرے۔
(ایف) اس بات پر غور کرے کہ ا س قرارداد اور قرارداد ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کے ذریعے عائد کردہ اقدامات پر مکمل اور موثر عملدرآمد پر زور دینے کے لیے کمیٹی کے چیئرمین اور دوسرے ارکان کا علاقے کے رکن ملکوں کا ایک دورہ مناسب ہے۔
(جی) کمیٹی وقتا "فوقتا "اس قرارداد اور قرارداد ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کے بارے میں ملنے والی اطلاعات اور ممکنہ خلاف ورزیوں کے بارے میں رپورٹیں اور اقدامات کو موثر اور مضبوط کرنے کے لیے سفارشات بھیجتی رہے۔
۱۷۔ تمام رکن ممالک اقوام متحدہ اور اس کے خصوصی اداروں سمیت تمام علاقائی اور بین الاقوامی ادارے قرارداد کی شقوں پر سختی سے عملدرآمد کریں اگرچہ پیرا گراف نمبر پانچ، آٹھ، دس اور گیارہ میں مذکورہ اقدامات کے نفاذ کی تاریخ سے قبل ان اداروں اور افغانستان کے درمیان کوئی بین الاقوامی معاہدہ یا مفاہمت ہی موجود کیوں نہ ہو ،انہیں کوئی اجازت نامہ اور لائسنس ہی کیوں نہ جاری کیا گیا ہویا ان پر کسی طرح کے فرائض کی بجا آوری لازم ہی قرار کیوں نہ دی گئی ہو۔
۱۸۔ تمام ممالک ایسے افراد اور اداروں کے خلاف اپنے دائرۂ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کی جانے والی کارروائی سے آگاہ کریں جو پیراگراف پانچ، آٹھ، دس اور گیارہ میں مذکور اقدامات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہوں اور ان پر مناسب جرمانے عائد کریں۔
۱۹۔ رکن ممالک کمیٹی کے اہداف کے حصول کے لیے اس سے مکمل تعاون کریں اور کمیٹی کو قرارداد کے نفاذ کے لیے جو اطلاعات درکار ہوں، وہ فراہم کریں۔
۲۰۔ تمام ممالک قرارداد کے نفاذ کے ۳۰ یوم کے اندر کمیٹی کو آگاہ کریں کہ انہوں نے قرارداد کے موثر نفاذ کی خاطر کیا اقدامات کیے ہیں۔
۲۱۔ سیکرٹریٹ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ حکومتی اور عوامی ذرائع سے قرارداد کی ممکنہ خلاف ورزی کے بارے میں موصول ہونے والی اطلاعات کمیٹی کو جائزہ لینے کے لیے بھیجیں۔
۲۲۔ پیراگراف پانچ، آٹھ، دس اور گیارہ میں مذکور اقدامات قرارداد کی منظوری کے ایک ماہ بعد ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات ایک بجے نافذ ہو جائیں گے۔
۲۳۔ پابندیوں کا نفاذ ایک سال کے لیے ہے۔ اس کے بعد کونسل فیصلہ کرے گی کہ آیا طالبان نے پیراگرف ایک، دو، تین پر عملدرآمد کیا ہے یا نہیں اور یہ کہ مزید اتنی ہی مدت کے لیے پابندیوں میں انہی شرائط کے ساتھ توسیع کی جائے یا نہیں۔
۲۴۔ اگر طالبان ایک سال سے کم عرصہ میں ہی شرائط پوری کر دیتے ہیں تو سیکورٹی کونسل نافذ کیے گئے اقدامات واپس لے لے گی۔
۲۵۔ کونسل اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے موجودہ قرارداد اور ۹۹ء میں منظور ہونے والی قرارداد نمبر ۱۲۶۷ کے اہداف حاصل کرنے کی خاطر مزید پابندیوں کے نفاذ پر بھی غور کرے گی۔
(بشکریہ جنگ لاہور، ۲۱ دسمبر ۲۰۰۰ء)
اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات
ادارہ
اسلام آباد (خبر نگار) اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر شیر محمد زمان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جمعہ کی چھٹی کو ختم کرنے کا غلط فیصلہ واپس لیا جائے۔ مقام حیرت ہے کہ جمعۃ الوداع کی تعطیل قیام پاکستان سے لے کر میاں نواز شریف کے دوسرے دور اقتدار تک ہوتی رہی مگر حکومت نے اس زیادتی کی تلافی بھی ضروری نہیں سمجھی۔ انہوں نے یہ بات اسلامی نظریاتی کونسل کے ۱۴۱ ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ۴ جولائی ۱۹۷۷ء کے بعد نافذ ہونے والے قوانین کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری کے حالیہ مفصل شق وار جائزہ کے باوجود کونسل قرآن وسنت اور اسلامی تاریخی کی روشنی میں سچے اور فوری انصاف کی فراہمی اور اسلامی قوانین کے ثمرات کو ممکن الحصول بنانے کے لیے ضابطہ مرتب کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہاپاکستان میں نافذ ہونے والے قوانین حدود وقصاص ودیت پر مختلف حلقوں کے اعتراضات اور مبینہ بد عنوانیوں اور خواتین سے مبینہ امتیازی سلوک کی شکایات پر ایک کمیٹی ان کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کونسل کے اخراجات ۹۷۔۱۹۹۶ء کی نسبت ایک تہائی رہ گئے لہذا پری آڈٹ کا وہی نظام کونسل میں رائج ہونا چاہئے۔ ڈاکٹر شیر محمد زمان نے کہا کہ کونسل کی سفارشات کے عملی نفاذ کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کونسل پہلے بھی یہ پیش کش کر چکی ہے کہ آئندہ قانون سازی میں قرآن وسنت سے متعارض کوئی عنصر شامل نہ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے آرٹیکل (۱) ۲۲۷ کے تحت یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ ہر بل مقننہ کے سامنے پیش ہوتے ہی متعلقہ مجلس قائمہ کے ساتھ ساتھ کونسل کو بھی بھجوا دیا جائے تاکہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کے بارے میں کونسل کی رائے بھی ایوان کے سامنے آ جائے۔ لیکن ہماری اس تجویز پر باضابطہ توجہ نہیں دی گئی اگرچہ بعض بل کونسل کو بھجوائے گئے۔ مثلا انفساخ نکاح مسلمانان ایکٹ کا ترمیمی بل ۱۹۹۹ء، انسانی اعضاء کے عطیہ وپیوند کاری کے مجوزہ آرڈیننس ۲۰۰۰ء کا مسودہ بھی حال ہی میں کونسل کی رائے معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ان تجاویز کو پذیرائی بخشی جائے تو قوانین کی اسلامی تشکیل کے عمل میں خاصی سہولت اور تیزی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک مختلف علوم وفنون کے نصاب کو اسلامی تعلیمات وفلسفہ حیات اور پچھلی چودہ صدیوں میں مسلم مفکرین کی فکر سے روشناس کرانے کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ کونسل نے اپنے مخصوص دائرہ کار کی ترجیحات کے پیش نظر تدریس قانون کے سہ سالہ نصاب کی اسلامی تشکیل پر بھرپور توجہ دی ہے۔ پاکستان میں قانون کی تمام درسگاہوں کے فلسفہ ومقاصد میں ایسے انقلاب کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ۲۴ پرچوں کے مفصل نصاب پر مشتمل ہمارا تجویز کردہ سہ سالہ نصاب برائے لاء کالجز فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ یہ صورت حال ہرگز قابل قبول نہیں کہ ہمارے لاء کالجز سے ایسے قانون دان فارغ ہو کر نکلیں جو عربی زبان کی شد بد بھی نہ رکھتے ہوں اور اسلامی قوانین سے نابلد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بلاشبہ معاشرتی سطح پر خواتین کے حقوق کا تحفظ ہماری ترجیحات میں سرفہرست ہونا چاہئے اور ہمیں اپنے پورے وسائل بروئے کار لا کر اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ اسلام نے ہماری خواتین کو جو حقوق عطا کیے ہیں انہیں غصب کرنے کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں۔ اسلام کسی بھی معاملے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا اور قتل کو قتل تصور کرتا ہے اگرچہ اسلامی آداب معاشرت ،احترام والدین، حیا داری وعزت نفس کی قدریں بھی ہمارا سرمایہ حیات ہیں۔ سوشل ورک، بالخصوص خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو اگر صحیح معنوں میں خلوص نیت کے ساتھ کسی طرح کے مفاد، لالچ یا کسی طرح کی بیرونی تحریک یا دباؤ کے بغیر خواتین کے حقوق کی بحالی مقصود ہے تو ان اداروں میں کام کرنے والی خواتین خود کو اسلامی حقوق کی بحالی کے لیے وقف کر دیں۔
سپریم کورٹ کے فیصلہ کے تحت پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی کی سربراہی میں قائم ہونے والی ٹاسک فورس پچھلے سات آٹھ مہینوں سے امتناع ربا آرڈیننس کے مسودہ کی تیاری اور اس کے عملی مضمرات پر نہایت احتیاط، فکری گہرائی اور جزئیاتی تفاصیل کے ساتھ غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوانین وضوابط سے یہ نظام وجود میں نہیں آئے گا۔ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے دائرہ کار میں دیانت وامانت کا وہ مفہوم سختی کے ساتھ اپنانا ہوگا جو ہمارے سرور کائنات حضرت محمد ﷺ کی مبارک تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حکومتی اقدامات سے بھی یہ واضح ہو نا چاہئے کہ ہم اجتماعی طور پر اس سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے بیرون ملک متوطن پاکستانیوں کے پاکستان میں فارن ایکس چینج اکاؤنٹ منجمد کر کے اصول دیانت کی خلاف ورزی کے ساتھ ان کے اعتماد کو ناقابل تلافی صدمہ پہنچایا۔ موجودہ حکومت بہرحال اس حکومت کی جانشین اور اس کی ذمہ داریوں کی وارث ہے لہذا ہمیں کسی تحفظ یا ہچکچاہٹ کے بغیر اس دھاندلی پر غیر ملکوں میں مقیم پاکستانیوں سے غیر مشروط معافی مانگنی چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور پاکستانی ثقافت کے احیا اور اس کی ترویج وسرپرستی کے حوالے سے ہمارے ذرائع ابلاغ برابر ایک منفی کردار ادا کر رہے ہیں اور سرکاری الیکٹرانک میڈیا اس کردار میں پیش پیش ہے۔ خود انحصاری کے نام پر، غیر ملکی ٹی وی چینلز سے مقابلہ کی آڑ میں لباس، چال ڈھال، رہن سہن، گفتگواور معاشرتی رویوں کے ایسے ماڈل ٹیلی ویژن پر ڈراموں، کلچرل شوز، موسیقی کے پروگراموں اور سب سے بڑھ کر اشتہارات کے ذریعہ سے پیش کیے جا رہے ہیں جو ہماری اخلاقی اقدار اور معاشرتی آداب کے تقدس کو تہس نہس کرنے کے ساتھ ان منفی رویوں کو دلکشی کے ساتھ پیش کر کے گمراہی، احساس محرومی اور جرائم کے ارتکاب کی آبیاری کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اصلاح بالخصوص سرکاری ذرائع ابلاغ کی اصلاح ایک ایسا پروگرام ہے جو کسی بھاری بجٹ کا متقاضی نہیں۔ اس کے لیے صرف سوچ درست کرنے اور عزم صمیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بلاشبہ اسلام میں ہفتہ میں ایک دن کی لازمی چھٹی کا کوئی تصور نہیں مگر ہفتہ وار چھٹی کے لیے دن کا تعین ناگزیر ہو تو اسلامی ریاست میں جمعہ کو فیصلہ کن ترجیح حاصل ہے۔ بہرکیف قومی یکجہتی اور مسلم معاشرہ کے شعار کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ جمعہ کی چھٹی کو ختم کرنے کا غلط فیصلہ واپس لیا جائے۔
(مطبوعہ روزنامہ نوائے وقت راولپنڈی، ۱۰ جنوری ۲۰۰۱ء)
دجال ۔ ایک تجزیاتی مطالعہ
پروفیسر غلام رسول عدیم
دینی موضوعات پر لکھنا اور تحقیق وتفحص سے لکھنا کنج کاوی بھی چاہتا ہے اور تلوار کی دھار پر چلنے کے فن کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ تاہم اس پژوہش کاری اور احقاق حق کے لیے جان مارنے والے کو جب تخلیقی راہیں سوجھنے لگتی ہیں تو اس کی تحریر میں بلا کا بانکپن اور غضب کی دلکشی آجاتی ہے۔ اس کشش وانجذاب میں قاری بسا اوقات بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ از خود گرفتہ ہو کر محقق کے سامنے خود انداز وخود سپر ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے سوا اس کے پاس چارۂ کار ہی نہیں رہ جاتا۔
بلاشبہ منقولات کا استحکام اپنی جگہ کوہستانی سلسلوں کی صلابتیں رکھتا ہے مگر کبھی معقولاتی ہپناٹزم سے منقولات کی ساری دیواریں گرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں (اگرچہ اصلا " وہ گر نہ رہی ہوں مگر معلوم ضرور ہوتی ہیں) جب سحرکار محقق اپنے سارے بارود سے خطرناک بارودی سرنگیں (mines) بچھا دیتا ہے تو قاری بے چارے کی کبھی ٹانگ بھک سے اڑتی ہوئی نظر آتی ہے تو کبھی بازو۔ کبھی اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے تو کبھی سارا جسم متاثر ہو کر ہمیشہ کے لیے اسے اپاہج کر دیتا ہے اور کبھی محقق کی تعقلاتی واستدلالی برنائیاں انسانی ذہنوں کو وہ اچھوتے خیالات اور ان ہونے افکار (جو ناموجود ہی رہتے تو بہتر تھا) دے جاتی ہیں کہ منقولات اپنی صلابتوں کے باوجود ریزہ ریزہ اور اپنی اعماق کے باوجود اتھلی اتھلی سی نظر آنے لگتی ہیں۔
کچھ عرصہ قبل زیر نظر کتاب ’’دجال‘‘ واجب الاحترام مولانا زاہد الراشدی نے بڑی محبت سے عنایت کی اور اس پر لکھنے کا حکم بھی دیا۔ عنوان دیکھا، سرسری طور پر کتاب کو دیکھا، ذیلی عنوانات نے چونکا یا تو ضرور مگر سنبھال کر رکھ دی کہ اس موضوع پر پڑھنے یا لکھنے کا موقع آیا تو دیکھا جائے گا۔ اسی اثنا میں مولانا عازم یورپ ہو گئے، راقم بھی سمجھا کہ حکم ٹل گیا۔ اب بشرط فرصت مطالعہ ہو جائے گا مگر ان کی واپسی پر وہی تقاضا دہرایا گیا تو اب جائے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ تھا۔ وعدہ کر لیا۔ والکریم اذا وعد وفیکتاب نکالی، مطالعہ شروع کیا تو معلوم ہوا کہ طائرانہ نگاہ سے کام نہ چلے گا، غواصانہ طرز عمل اپنانا ہوگا۔ آگے پیچھے وقت نکال نکال کا استیعابا " ومستوعبا " مطالعہ شروع کر دیا۔ دوران مطالعہ پتہ چلا کہ مصنف کی گیارہ کتابیں مطبوع ہیں۔ پس ورق پر دی فہرست دیکھ کر جی میں آئی کہ کاش یہ کتابیں بھی کسی طرح ہاتھ آئیں تو ان کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ پھر خیال آتا کہ مولانا موصوف ہی سے اس ضمن میں درخواست کی جائے گی۔
بہر صورت کتاب ’’دجال‘‘ کے مصنف سے متعلق نادیدہ تاثر وتعارف تو کچھ یوں ہے کہ جناب اسرار عالم کا علمی تبحر مسلم اور وسعت نظر قابل رشک ہے۔ قدیم وجدید پر ان کی علمی وفکری گرفت قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی۔ ان کی علمیت کی گہرائی اور معلومات کا وفور کتاب کے صفحے صفحے بلکہ لفظ لفظ سے جھلک رہا ہے۔ انداز بیان، مفہوم المراد اور اسلوب کی دل آویزی قاری کو مسحور کیے دیتی ہے۔ تاہم انجام کار تک پہنچتے پہنچتے تحقیق وپژوہش کی ریزہ کاریاں خود رائی اور خود آرائی کی حدوں کو چھوتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہیں۔
کتاب کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو پھر مختلف حصوں اور مراحل میں بانٹا گیا ہے۔پہلے باب میں عالم موجود میں دجال کی نمایاں ترین اشکال پیش کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی فکری اور سیاسی ساخت وبافت اور ا س کے ہیئتیانسجام کو مدلل انداز میں پیش کر کے ا س کے پیچھے یہودی قوتوں کی کارفرمائی کو بجا طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔
جدید اصطلاحات پیش کر کے پوری قوت استدلال کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق، معاشی بحران، عالمی مالیاتی اداروں اور قانون کی حکمرانی وغیرہ کے اصل رائج الوقت مفہومات کیا ہیں۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہیں کس دجل اور دسیسہ کاری کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ عصر حاضر کا سب سے بڑا دجال ہے جو Global Civic Ethics او ر Total demilitarization of States کے ذریعے پورے روئے ارض کی ہر دجال حکومت کا ممد ومعاون ہے۔ اس خیال کو تقویت دینے کے لیے مصنف نے جو تاثیر وتاثر میں ڈوبا ہوا توضیحی وترغیبی اسلوب بیان اختیار کیا ہے، اس میں شعور وآگہی کے جملہ وسائل استعمال کیے ہیں۔ تاریخ عالم سے استناد اور عصر حاضر کے جدید ترین فکری رویوں کے نیچے یہودی عزائم کے مضمرات، امریکی بھارتی باہمی دلچسپیاں بلکہ مسلم دشمنی کے لیے گہری چسپیدگیاں، کلنٹن سبرامینیم کی فکری زہر چکانیاں بڑے ہی تلخ حقائق کے طور پر پیش کی ہیں۔
’’اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے یہ خطہ ایک ہزار سال کے اجتماعی امن کے بعد پھر قتل عام اور بڑے پیمانے پر عوامی بیدخلی Mass Exodus کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کا تلخ تجربہ بھارت نے بطور خاص دوسری صدی عیسوی اور نویں صدی عیسوی کے مابین کیا تھا۔‘‘ (ص ۳۴)
عیسائی یہودیوں یا یہودی عیسائیوں کے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے، ختم کرنے یا کم از کم زاویہ نشین کر دینے کے فری میسنری منصوبوں کو غیر مبہم اعداد وشمار سے واضح کیا ہے۔
اس دوران میں مصنف نے سطر سطر میں معلومات عامہ کے دھارے بہا دیے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی سوچ اپنی اور مآخذ اصلی ہیں۔ قاری کی آسانی کے لیے وہ دوسری زبانوں کے واضح اقتباس دے کر بڑا ہی رواں ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے یہ تبصرے ۲۰۰۰ء تک کے یہودی عزائم کے جاندار تجزیے ہیں۔ عالم اسلام بالخصوص پاکستان کو جس سنگین حصار میں محصور کیا جا رہا ہے، اسے اور اکیسویں صدی، ترقی ومسابقت وغیرہ کے خوشنما ناموں کے پردے میں کی جانے والی منظم کوششوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ باقاعدہ جریدی اقتباسات سے اپنے موقف کی بھرپور تائید لائی گئی ہے۔ اس باب کے آخر میں ائمۃ المضلین کے عنوان سے حضرت مجدد الف ثانی ؒ ، حضرت شاہ ولی اللہؒ او ر علامہ اقبال ؒ کی دینی وملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان علما کی سخت مذمت کی ہے جو ’’اہل حکومت، اہل ثروت، اہل سیاست اور جہلا کے بواب‘‘ بننے پر قانع ہو گئے۔
باب دوم میں ستارہ وصلیب کے عنوان سے یہود ونصاری اور مسلمانوں کے ایک محوری نقطے یعنی آمد مسیح، ظہور دجال اور حکومت عدل کے قیام کو موضوع بنایا ہے۔ان تینوں عقائد کو اپنی تحقیق کے مطابق متعلقہ مذاہب کے نوشتوں سے استنباط کر کے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کو مرحلہ وار پیش کیا ہے۔ آمد مسیح کے تصور کو جس طرح انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے ، ان اجزا کی ترتیب کچھ یوں ہے:
’’اللہ اور اللہ کے ملائکہ سے مایوسی، ساری دنیا سے غصہ اور نفرت، اپنی طاقت اور ابلیس اور ا س کے دجالوں کی مدد سے کھوئی ہوئی چیزوں اور آئندہ کی بشارتوں کو حاصل کرنے کی کوشش‘‘
’’ساری دنیا کے یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، وہ دراصل دجال اکبر یعنی مسیح الدجال ہے‘‘
مصنف نے یہ بات بھی علی الاعلان کہی ہے کہ یہودی دینی ادب دجال کے ذکر سے خالی ہے۔ اگر کہیں کوئی شائبہ ہے بھی تو اسے تاویلات سے رد کر دیا گیا ہے۔
روئے ارض پر نظام عدل کے قیام کے سلسلے میں ’’ہایوم‘‘ کی کم از کم ۹ جدا جدا تاویلات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی رو سے مسیح یعنی دجال اکبر کی آمد پر خوشحالی کے دن آئیں گے۔ مسیح کے دن کو دجال اکبر پر منطبق کر کے قیام اسرائیل اور دجالی تہذیب کو یسعیاہ نبی کے قول سے جوڑ دیا ہے۔
جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، ان میں پروٹسٹنٹوں کی عیسائیت تو یہودی امتزاج مسیحیت ہے البتہ رومن کیتھولک Second coming of Jesus کو مانتے ہیں۔ اس کے لیے مصنف نے اناجیل اربعہ سے اقتباسات دے کر اپنے موقف کو خاصا وزنی بنایا ہے۔ اس بات کو کھل کر بیان کیا ہے کہ دجال کے ظہور کے بارے میں متناسب اناجیل متی ،مرقس اور لوقا خاموش ہیں حالانکہ آمد مسیح کے بارے میں ان میں خاصا مواد موجود ہے۔ یوحنا میں واضح اشارات کاذکر کیا ہے۔ Anti Christ (مخالف مسیح) Man of lawlessness (لاقانونیت کاآدمی) Son of perdiction (تباہی کا بیٹا) مسیحیت میں اس کی صفات جھوٹا، فریبی، خدائی کا دعویدار، حیرت ناک کرشمے دکھانے والا، دین مخالف، تباہی لانے والا اور مخالف خدا وغیرہ ہیں۔ یہ صفات بہت حد تک دجال سے ملتی جلتی ہیں۔
قیام عدل Kingdom of God (حکومت الہیہ) کے سلسلے میں مسیحی نوشتوں سے اخذ واستفادہ کے بعد مصنف نے ’’موجودہ عیسائیت‘‘ کو اس قافلے سے تشبیہ دی ہے جو اپنے قافلہ سالار سے بچھڑ گیا ، راہزنوں (یہودیوں) کے چنگل میں آ گیا اور لوٹا گیا، پھر دوسرا جتھہ آیا اس نے معصوم بنتے ہوئے غلط راستوں پر لگا دیا۔ ا س راستے پر ڈال دیا جو اس ملک کو جاتا تھا جہاں غلاموں کی خرید وفروخت ہوتی۔ راہزن جانتے تھے کہ انہیں وہاں لے جا کر بیچ دیا جائے گا۔ مصنف کے بقول اب سیدنا مسیح آئیں گے تو موجودہ مسیحی دنیاپال کے دین کے بجائے ان کے دین پر ہوگی۔ یہی معنی ہے فیکسر الصلیب کا۔
تیسرے باب میں حقیقت دجال کے عنوان سے اسلام کا نقطہ نگاہ دجال سے متعلق پیش کیا ہے۔ یہی وہ مرکزی باب ہے جہاں مصنف کی طبیعت کے تحقیقی بلکہ تخلیقی جوہر کھلے ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کی کائنات کے بارے میں قرآنی سند کے ساتھ چار مدارج سے بحث کی ہے جو خاصی دلچسپ ہے۔
عالم اصل جس کے بارے میں مصنف متردد ہیں کہ وہ ہے بھی یا نہیں، پہلا عالم قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا عالم عالم بریہ، تیسرا عالم عصر اور چوتھا عالم اشیاء ہے۔ آخری عالم ہی محل تکلیف ٹھہرا کر مجرائے دین اللہ قرار دیا ہے۔ ان عوالم کی تشریح میں آیات قرآنی سے استخراجا " بڑا زور دیا ہے۔
حقیقت دوم میں ابلیس، شیاطین وغیرہم کی حقیقت پر بحث کی ہے۔ ملائکہ، جنات اور آدم کی تخلیق کو ابنائے نور، ابنائے نار اور ابنائے ارض کے عنوانات کے تحت پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں ملائکہ کی صفات کے مطابق انہیں Categorize کر دیا ہے ۔ انواع نار کی تقسیم کر کے فرماتے ہیں ’’عالم اشیاء سے انواع نار کی بڑی آبادی کا تقریبا خاتمہ ہو گیا‘‘ (ص ۲۰۴) پھر ا س کلی تباہی کے خود ساختہ اسباب بھی گنوائے ہیں جو ایجاد بندہ قسم کی چیز ہے۔ (ص ۲۰۵) شیاطین کی انواع گنوائی گئی ہیں۔ ملائکہ کی طرح قرآن مجید یا احادیث نبوی سے ان کی صفات چن چن کر ان کو انواع بنا دیا ہے۔
حقیقت سوم کے عنوان سے معرکہ خیر وشر کو موضوع بنا کر مصنف نے طبیعت کی خوب خوب جولانیاں دکھائی ہیں۔ فرماتے ہیں:
’’کائنات میں معرکہ خیر وشر کے آخری مرحلے کا باضابطہ آغاز اسی لمحے ہو گیا جب اللہ تعالی نے ابلیس کو یوم وقت معلوم تک کی اجازت دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا : قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم (الحجر ۳۷، ۳۸۔ ص ۸۰، ۸۱) جواب میں اللہ نے فرمایا : لاملئن جھنم منک وممن تبعک منھم اجمعین ‘‘ (ص ۸۰)
اس سارے مضمون کو پوری شرح وبسط کے ساتھ بڑے ہی پرزور استدلال سے پیش کیا ہے۔ انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کو خوبصورتی سے justify کیا ہے۔ فی الارض خلیفۃ سے مراد لیاہے ’’اہل زمین میں سے‘‘ ابنائے نور اپنی امیدیں لگائی بیٹھے تھے اور ابنائے نار اپنی ۔ ’’حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کو صرف اسما سکھائے اور اشیاء نہیں دکھائیں اور ملائکہ کو اشیاء دکھائیں اور نام پوچھا‘‘ (ص ۴۴۸) یہ تاویل بھی خاصی انوکھی ہے۔
باب چہارم میں معرکہ خیر وشر کی تاریخ مرحلہ وار بیان کی ہے۔ مرحلہ اول میں آدم قدیم، مرحلہ دوم میں الجنۃ کا وہ دور جب اللہ نے آدم کے جسم سے حوا کو الگ کر دیا۔ عام ڈگر سے ہٹ کر لا تقربا ہذہ الشجرۃ (البقرہ ۳۵) کا ترجمہ کیا ہے ’’اور پاس مت کرنا اس شجر کو‘‘ (ص ۲۶۲) ’’آدم وحوا اس الشجرۃ کو قریب کر بیٹھے اور انہیں اس کا مزہ مل گیا‘‘ (ص ۲۶۴)
مفسرین سے اختلافی آواز بلند کرتے ہوئے لکھتے ہیں
’’قرآن کی ا س عبارت سے مراد لینا جیسا کہ بیشتر مفسرین نے لیا ہے کہ وہاں کوئی پھل یا اناج کھانے کی کوئی چیز تھی، قرآن کی زبان اور بیان کے خلاف ہے‘‘ (ص ۲۶۷)
’’انہوں نے وہ عمل کر لیا جسے ’’جماع‘‘ کہتے ہیں۔ ان کی زندگی میاں بیوی کی تھی، ایسا قطعا نہیں تھا‘‘ (ص ۲۶۸)
ان سطور پر تبصرہ تحصیل حاصل ہے۔ معلوم نہیں مصنف میاں بیوی نہ ہونے کے باوجود آدم وحوا کو جماع کے عمل میں ملوث کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان سنگین الفاظ کے لیے ان کے پاس کیا جواز ہے:
’’ممکن ہے دونوں کی صورت یہ ہو کہ دونوں کے جسم ہوں اور ان دونوں کے دو جانب یعنی اوپر اور نیچے دو دو سوراخ ہوں یا یہ کہ اوپر کے دو سوراخ کھلے ہوں اور دونوں کے نیچے کے دو سوراخ
تو ہوں مگر ا س پر کوئی بندش، پنبہ یا پردہ لگا ہو‘‘ (ص ۲۶۹)
کھل نہیں سکا کہ مصنف کو ایسے لاطائل مفروضات کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ ان امکانات میں آخر پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
’’چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ عمل نہ صرف ایک عمل تھا بلکہ ایک ایسا عمل تھا جس نے الجنۃ کے پورے نظام کو blast کر دیا‘‘ (ص ۲۶۹)
پھر بجلی کے تاروں کی مثال دی ہے کہ خلاف قاعدہ ملیں تو شارٹ سرکٹ ہو جانے پر دھماکہ ہو جاتا ہے۔
’’ایسا لگتا ہے حضرت حوا اس یا ان مقاربت سے حاملہ ہو گئیں اور استنساخ Cloning پر بنائی گئی الجنۃ میں ابذار Insensation کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہی برآمد ہوتا کہ وہاں استنساخ سے تولید کی سنت تو تھی لیکن ابذار سے ہونے والی تولید کا نظم کرنا الجنۃ کی سنت کےخلاف تھا اور نتیجتا " وہاں فساد برپا ہوتا‘‘
’’الجنۃ سے نکلنے کا بنیادی سبب یہی غیر صالح حمل کے سوا کچھ نہ تھا‘‘ (ص ۲۷۲)
یہ ہے تحقیق جس سے معرکہ خیر وشر میں ’’آدم وحوا سخت تباہ کن حالات سے دوچار ہوئے‘‘ (ص ۲۷۹)
مرحلہ سوم میں آدم وحوا زمین پر دکھائے گئے ہیں۔ ولادت قابیل کو جنت کا ناجائز حمل قرار دیا گیا ہے۔ ولادت زمین پر ہی ہوئی مگر وہ ’’نہ جنتی مخلوق آدمی تھا نہ ارضی مخلوق آدمی‘‘ ہابل البتہ ارضی جائز اولاد تھا۔’’قابیل وہابیل کی لڑائی اور اس کے لیے بہن پر جھگڑا سب افسانے ہیں‘‘
حضرت شیث اور دیگر اولاد آدم وحوا کے بارے میں رقم طراز ہیں:
’’اسی طرح یہ لوگ اگرچہ آدمی تھے مگر زمینی ہونے کے اعتبار سے آدھے تھے اور ابھی تک پوری طرح زمینی نہیں ہوئے تھے‘‘
رانش بن شیث پہلے مکمل زمینی انسان تھے۔ پھر پورے یقین کے ساتھ ان کی عمریں گنوائی ہیں۔توضیحات میں حضرت ادریس ہی کو الیسع کہا گیا ہے۔ پھر ذو الکفل کو نصرت کفل کے تانے بانے میں لاکر عجیب طرح سے صفت ادریس قرار دیا ہے۔ پھر ادریس، الیسع اور ذو الکفل کو ایک ہی شخصیت قرار دیا ہے۔ ایسی ہی تحقیق انیق ذو القرنین سے متعلق ہے۔ انہیں بھی صفت مان کر ادریس قرار دیا ہے۔
’’ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار سالوں کے اندر اندر ہی اللہ تعالی نے ایک بار پھر حضرت ادریس کو جنہیں پہلے مرحلے میں ذو الکفل بنایا گیا تھا، ذو القرنین کے اعتبار سے مبعوث فرمایا‘‘ (ص ۳۱۷)
ع جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
’’غور کرنے سے ایسا لگتا ہے‘‘ ، ’’اس عاجز کی رائے یہ ہے‘‘ ، ’’اس عاجز کا رجحان اسی جانب ہے‘‘، ’’اس عاجز کی رائے میں‘‘ ، ’’اس عاجز کا احساس ہے‘‘، ’’اس عاجز کا خیال ہے‘‘، ’’ اس عاجز کی تحقیق کے مطابق‘‘ یہ ہیں وہ الفاط جن کے بعد پوری علمی وجاہت اور زور تحقیق سے موصوف وہ وہ کیفیات وواقعات تخلیق کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم جیسے عاجز تو ان کے سمجھنے سے عاجز ہی رہ جاتے ہیں۔ فساد عقیدہ میں شرک اور فساد طبع کے تحت انسانی آبادی کو تباہ کرنے کے لیے زنا بین المخلوقات اور زنا بین الانسان کے ضمن میں تحریر فرمایا ہے:
’’ملک شیاطین اور جن شیاطین ابلیس کے ساتھ برابر کے شریک تھے چنانچہ وہ بطور خاص آدمی خواتین پر حملہ آور ہوئے اور ان سے زبردستی یا انہیں قابو میں لاکر یا ان سے روابط بڑھا کر ان کے ساتھ طبعی ازدواجی تعلقات پیدا کر لیے اور اس اختلاط اور زنا کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین پر بین المخلوقاتی نیم انسانی ملکی یا نیم جنیاتی خلاف طبعی حرام نسل کی پیدائش کا آغاز ہوا‘‘
شیاطین کی اقسام کے طور پر جبار نفل الیو، نفر اور عفریت کی خود ساختہ تقسیم کر کے من مانی توضیحات کی ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابلیس کی غضب ناکی کا اظہار کرتے ہوئے جوموصوف کے خلاق ذہن اور طبع رسا نے واقعہ گھڑا ہے، قابل دید ہے:
’’وہ اپنی کوششوں سے ملائکہ کے ایک گروہ کو گمراہ کرنے اور اپنے ساتھ ملانے اور انہیں آدم کے خلاف اپنی جنگ میں آلہ کار بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے (معلوم نہیں کو ن کہتا ہے اور موصوف نے کس سے سنا ہے، اس قول کا پایہ استناد کیا ہے) کہ یہ دو سو سے زائد ملائکہ تھے جن میں انیس اعلی درجے کے ملائکہ تھے۔ ابلیس نے ان کے اندر فساد جنس پیدا کیا اور انہیں زمین پر لے آیا۔ ابلیس کی کوششوں سے ان ملائکہ نے انسانی عورتوں سے صحبت کی اور بے قابو ہو گئے‘‘ (ص ۳۲۷)
ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے
خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھئے
اقوام عالم میں قرآن مجید نے بغرض عبرت آموزی جن اقوام کی تاریخ سے اعتنا کیا ہے، ان میں عرب بائدہ کی دو معروف قومیں عاد اور ثمود بھی ہیں۔ مفسرین ومورخین نے تاریخ، کتبات اور آثار حفریات سے ان قوموں کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں، ہمارے محقق نے ان سب کو مسترد کر کے اس سارے علمی خزانے کو بیک جنبش قلم دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تک قوم عاد کا مسکن جنوبی عرب میں احقاف کے ریگزار رہے ہیں جن کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ثمود کا مسکن شمالی عرب میں الحجر کا علاقہ مانا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس تحقیق کے مطابق :
’’قوم عاد کا مسکن بابل کے شمالی ضلع کے دار السلطنت عاد کے نام سے مشہور ہوئی‘‘
جس کے حدود سلطنت کا تعین یوں کیا گیا ہے
’’مصر، شمال میں آرمینیا اور ایشیا کوچک تک ،جنوب میں یمن اور مشرق میں سندھ تک۔ وادی سندھ کی تہذیب دراصل عاد کی تہذیب یا اس کی توسیع تھی‘‘ (ص ۳۵۰)
’’اس عاجز کی تحقیق کے مطابق یہ تہذیب ثمودی تہذیب ہے جسے تاریخ میں مصر کی تہذیب یا وادئ نیل کی تہذیب The Nile valley civilization بلکہ مخصوص طور پر عہد ابرام The Pyramid Age کہتے ہیں‘‘ (ص ۳۵۵)
’’بات اہم یہ نہیں کہ وہ اونٹنی تھی؟ کہاں سے اور کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے آئی؟ کتنا پانی پیتی تھی؟ یہ سب افسانے بھی ہو سکتے ہیں‘‘ (ص ۳۶۰)
ع بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بو العجبی است
مصنف کے علمی شکوہ، طرفگئ خیالات، دانش وبینش کی نادرہ کاریوں کو تسلیم کرلینے کے باوجود یہ ہیں وہ تحقیق وجستجو اور فکری پژوہش اور ذہنی قلابازیوں کے نادر نمونے جو اس کتاب کے مطالعہ سے سامنے آتے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ مصنف کی علمی وتحقیقی کاوشیں غیر معمولی ہیں۔ وہ ژرف نگاہی کے اسلحہ سے لیس ہو کر نکتہ بنکتہ ومرحلہ بمرحلہ اس گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ایک محقق کا طرۂ امتیاز ہوتی ہے۔ لیکن اس فکری اڑان میں وہ کبھی کبھی حقیقت حال سے دور جا نکلتے ہیں۔کہیں اپنی وسعت علم کی اساس پر اور کہیں اپنی رائے کی خود رائی کے زور پر رائی کو پربت اور ذرے کوکوہ گراں بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی تحقیقی مساعی سے ماضی کے ایوانوں میں تزلزل اور مسلمات میں دراڑیں پڑتی نظر آتی ہیں۔ یوں احقاق حق کے بجائے اتلا ف حق کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ مفروضے پر عظیم الشان عمارت بنا دینے کا فن خوب جانتے ہیں اور لطف کی بات یہ کہ استناد قرآن وحدیث سے کر کے ایسی تاویلات پیش کرتے ہیں کہ قاری کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ معرکہ خیر وشر کے حصے میں تو موصوف نے ایسے اچھوتے خیالات اور من مانے انہونے تصورات دیے ہیں کہ اچھے بھلے صاحب ایمان کا بھی سر چکرا جاتا ہے، پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں اور ایمان وایقان میں بے نام سے کسمساہٹیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔
دوبئی میں چند روز کی حاضری
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
رمضان المبارک کے بعد چند روز کے لیے دوبئی جانے کا اتفاق ہوا اور دوبئی کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی دیگر امارات شارجہ‘ عجمان‘ راس الخیمۃ اور الفجیرہ میں بھی مختلف دینی وعلمی مراکز دیکھنے اور سرکردہ حضرات واحباب سے ملاقات وگفتگو کا موقع ملا۔ ہمارے پرانے دوستوں حافظ بشیر احمد چیمہ آف گکھڑ اور جناب محمد فاروق شیخ آف گوجرانوالہ نے میزبانی کی اور ان کے ساتھ مولانا مفتی عبد الرحمن اورچودھری رشید احمد چیمہ نے بھی بہت سے مقامات میں رفاقت سے نوازا۔
دوبئی کے بارے میں سنتے آ رہے تھے کہ بیروت کے بعد مغربی ثقافت کے بہت سے مظاہر نے وہاں کا رخ کر لیا ہے اور جوکچھ خانہ جنگی اور تباہی سے قبل بیروت میں ہوتا تھا وہ سب کچھ اب دوبئی میں ہونے لگا ہے۔ بعض اہم مراکز میں جا کر فی الواقع یہی تاثر ملا اور مختلف حضرات سے جس قسم کی کہانیاں سننے کو ملیں ان سے اندازہ ہوا کہ دوبئی ابھی پوری طرح بیروت بنا تو نہیں لیکن حالات کا رخ اسی جانب ہے اور عشرت وتعیش کی جو سہولتیں دوبئی کے بڑے ہوٹلوں اور تجارتی مراکز میں دی جانے لگی ہیں ان کی رفتار یہی رہی تو آج کے دوبئی کا بیس سال قبل کے بیروت سے شاید کچھ زیادہ فرق باقی نہ رہے مگر یہ سوچتے ہی ذہن کا رخ ادھر مڑ گیا کہ مشرق وسطی کا پیرس بننے کے بعد بیروت پر جو گزری ہے اور اسے مغربی کلچر کی آزادانہ نمائندگی کرنے کی جو سزا ملی ہے ‘ دوبئی کے ارباب حل وعقد کی نگاہوں سے یقیناًوہ اوجھل نہیں ہوگی اور انہوں نے اپنے اس خطہ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچ رکھا ہوگا۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ حسن ظن صحیح ثابت ہو اور بیروت کے عروج وزوال کی شاہراہ پر تیزی سے دوڑتے چلے جانے والے دوبئی کی بریکوں پر اس کے بہی خواہوں کا کنٹرول قائم رہے۔
البتہ تصویر کے دوسرے رخ کے طور پر دوبئی میں اچھے مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ مساجد میں نمازیوں کی رونق دیکھی‘ دینی درسگاہوں میں بچوں کو قرآن کریم اور ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرتے دیکھا اور دعوت وارشاد کے حوالہ سے مختلف اداروں کی سرگرمیاں سننے میں آئیں جس سے خوشی ہوئی کہ ابھی توازن زیادہ نہیں بگڑا اور خیرکا پہلو اپنی کشش ایک حد تک باقی رکھے ہوئے ہے۔
سب سے زیادہ خوشی مرکز جمعۃ الماجد للثقافۃ والتراث میں جا کر ہوئی جو دوبئی کے ایک عرب شیخ اور تاجر الشیخ جمعۃ الماجد نے ذاتی خرچ سے قائم کر رکھا ہے اور ۸۷ء سے مسلسل مصروف کار ہے۔ اس مرکز میں مختلف علوم وفنون پر تین لاکھ کتابیں ذخیرہ کی گئی ہیں‘ مخطوطات ونوادر کو جمع اور محفوظ کرنے کا اہتمام ہے جس کے تحت چھ ہزار اصل مخطوطات‘ دس ہزار مخطوطات کے فوٹو اور پچاس ہزار مخطوطات کے مائیکرو فلم محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ مرکز کے ساتھ کلیۃ الدراسات الاسلامیۃ کے نام سے تعلیمی ادارہ اور جمعیۃ بیت الخیر کے عنوان سے رفاہی ادارہ کام کر رہا ہے۔ مرکز میں ایک سو سے زائد افراد پر مشتمل عملہ کام کرتا ہے جس میں ایک بڑی تعداد مختلف علوم وفنون کے متخصصین کی ہے اور آفاق الثقافۃ والتراث کے عنوان سے ایک ضخیم اور وقیع سہ ماہی علمی مجلہ بھی شائع ہوتا ہے۔ اس مرکز میں زیادہ وقت گزارنے کی حسرت ہی رہی اور مرکز دیکھنے کے بعد سے دل مسلسل الشیخ جمعۃ الماجد حفظہ اللہ تعالی کے لیے دعاگو ہے کہ اللہ رب العزت ان کی ان علمی ودینی خدمات کو قبول فرمائیں اور عالم اسلام کے دیگر اصحاب خیر کو بھی ان کے اس ذوق کا حصہ دار بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین
جامعہ فاروقیہ کراچی کے شہید اساتذہ
کراچی میں اہل دین ایک بار پھر دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں اور اس بار نشانہ جامعہ فاروقیہ فیصل کالونی کراچی کے مظلوم اساتذہ بنے ہیں‘ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جامعہ فاروقیہ ملک کے معروف اور مرکزی علمی اداروں میں سے ہے جس کے مہتمم وفاق المدارس العربیۃ پاکستان کے سربراہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ ہیں اور اس طرح ایک بار پھر اہل حق کے ایک بڑے مرکز کو دہشت گردوں نے ہدف بنایا ہے۔
یہ اساتذہ تو تعلیم وتدریس کی دنیا کے لوگ تھے جن کا ان ہنگاموں سے کوئی عملی واسطہ نہیں تھا جو فرقہ واریت یا دہشت گردی کا باعث بنتے ہیں یا انہیں اس کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ ان مظلوم اساتذہ اور ان کے دیگر شہید رفقا کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ ایک دینی وعلمی مرکز سے وابستہ تھے اور خاموشی کے ساتھ قرآن وسنت اور دیگر دینی علوم سے نئی نسل کو آراستہ کر رہے تھے۔ ان کو نشانہ بنا کر دہشت گردوں کو اس سے زیادہ کیا حاصل ہوا ہوگا کہ ان کے مخالفانہ جذبات کو وقتی طور پر تسکین مل گئی ہوگی اور اس کارکردگی پر انہیں کہیں سے شاباش حاصل ہو گئی ہوگی لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس مذموم حرکت اور وحشیانہ کارروائی سے علم وتقوی کا وجود چھلنی کر دیا ہے۔
یہ لمحہ فکریہ ہے ملک کے ارباب فکر ودانش کے لیے اور اس بات کی دعوت فکر ہے کہ وہ علماء کرام اور دینی کارکنوں کے اس قتل عام کو روکنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کے حقیقی اسباب وعوامل کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی روک تھام کے لیے کوئی مثبت اور موثر حکمت عملی اختیار کریں۔
اللہ تعالی جامعہ فاروقیہ کراچی کے ان مظلوم شہدا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں اور ان کے پس ماندگان اور متوسلین کو صبر جمیل کی توفیق سے نوازیں‘ آمین یا رب العالمین۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’دنیا کی نامور خواتین‘‘
روزنامہ اوصاف اسلام آباد کے معروف کالم نگار جناب محمد اسلم کھوکھر نے دنیا کی ڈیڑھ سو سے زیادہ نامور خواتین کے حالات اور کارناموں کو اس ضخیم کتاب میں جمع کیا ہے جن میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریؓ سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک مختلف مذاہب‘ طبقات‘ اقوام اور شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی نامور خواتین شامل ہیں اور اس حوالہ سے اچھا خاصا تاریخی مواد اور معلومات اس میں سمو دی ہیں۔
ساڑھے چھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل یہ مجلد کتاب فکشن ہاؤس‘ ۱۸۔ مزنگ روڈ لاہور نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت چار سو روپے ہے۔
’’دینی مسائل اور ان کا حل‘‘
انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج روزنامہ کویت ٹائمز میں دینی مسائل کے حوالہ سے قارئین کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو مختلف دینی عنوانات پر مسائل واحکام اور معلومات کا ذخیرہ ہوتے ہیں۔ انہی سوالات وجوابات کا ایک ضخیم مجموعہ انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کویت نے شائع کیا ہے۔
صفحات ۶۱۰‘ کتابت وطباعت معیاری‘ مضبوط جلد‘ قیمت درج نہیں۔
پاکستان میں ملنے کا پتہ: (۱) جامعہ سراج العلوم‘ دار القرآن ڈیرہ اسماعیل خان (۲) ۳۹ سکندر بلاک‘ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
’’عالمی نظام سیاست واقتصاد اور افغانستان کی طالبان تحریک‘‘
مولانا خالد محمود نے یہ ضخیم کتاب طالبان کی اسلامی تحریک کے پس منظراور موجودہ عالمی اقتصادی وسیاسی صورت حال میں طالبان تحریک کی انقلابی حیثیت کو واضح کرنے کے جذبہ کے ساتھ لکھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے افغانستان کی تاریخ اور عالمی سیاسی واقتصادی حالات کے بارے میں معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے جو افغانستان اور طالبان کے موضوع پر مطالعہ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے بیش بہا تحفہ ہے۔
چھ سو سے زائد صفحات پرمشتمل یہ کتاب گوشۂ علم وتحقیق‘ المدینہ گارڈن‘ جمشید روڈ نمبر ۲ ‘ کراچی نے عمدہ طباعت اور مضبوط جلد کے ساتھ پیش کی ہے اور اس کی قیمت ۱۸۰ روپے ہے۔
’’مقالاتِ رحمانی‘‘
جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے سابق مہتمم حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن رحمہ اللہ تعالی کے مختلف مضامین ومقالات کو ان کے فرزند مولانا عزیز الرحمن رحمانی نے مقالات رحمانی کے عنوا ن سے مرتب کیا ہے جس میں مختلف اہم عنوانات پرمعلوماتی اور علمی مضامین شامل ہیں اور حضرت مفتی صاحب کا صدقہ جاریہ ہیں۔
صفحات ۴۰۰‘ عمدہ جلد‘ کتابت وطباعت معیاری‘ ناشر: المکتبۃ البنوریہ‘ علامہ بنوری ٹاؤن‘ کراچی
’’فقہی جواہر‘‘
دار العلوم لندن کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عمر فاروق کے مختلف مضامین کو القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد نوشہرہ صوبہ سرحد نے مندرجہ بالا عنوان کے ساتھ شائع کیا ہے اور اس میں طلاق‘ عقیقہ‘ اہل کتاب کا ذبیحہ‘ فوٹو گرافی اور دیگر ضروری معاملات پر شرعی احکام کو فقہی انداز میں واضح کیا گیا ہے۔
۶۶ صفحات کے اس کتابچہ کی قیمت ۴۵ روپے ہے۔
بسنت کا تاریخی پس مظر
حکیم افتخار یوسف زئی
بسنت منانے والے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جب موسم سرما رخصت ہوتا ہے اور بہا ر کی آمد آمد ہوتی ہے تو یہ تہوار منایا جاتا ہے جبکہ تاریخی حقائق اس کے خلاف ہیں۔
سکھ مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار نے اپنی کتاب پنجاب میں آخری مغل دور حکومت میں لکھا ہے کہ ۱۷۰۷ء تا ۱۷۵۹ء زکریاخان پنجاب کا گورنر تھا۔ حقیقت رائے سیالکوٹ کے ایک کھتری باکھ مل پوری کا بیٹا تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس جرم پر حقیقت رائے کو قاضی وقت نے موت کی سزا دی۔ اس واقعہ سے غیر مسلم آبادی کو شدید دھچکا لگا اور بڑے بڑے ہندو مہاشے اور سرکردہ لوگ زکریا خان گورنر کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کی سزا ئے موت معاف کر دی جائے لیکن زکریا خان نے ان کی سفارش ماننے سے انکار کر دیا اور ۱۷۴۷ء میں اسے موت کی سزا دے دی گئی۔
ہندوؤں کے نزدیک حقیقت رائے نے ہندو دھرم کے لیے قربانی دی۔ اس لیے انہوں نے پیلی (بسنتی) پگڑیاں اور ان کی عورتوں نے پیلی ساڑھیاں پہنیں اور اس کی مڑھی پر پیلا رنگ بکھیر دیا۔ بعد میں ایک ہندو کالو رام نے اس مڑھی پر ایک مندر تعمیر کروایا۔ جس دن حقیقت رائے کو موت کی سزا دی گئی اس دن کو پیلے رنگ کی نسبت سے بسنت کا نام دیا گیا۔ اس دن ملحقہ میدان میں پتنگ بازی بھی ہوئی اور حقیقت رائے کی یاد تازہ رکھنے کے لیے یہ بسنت ہندو تہوار کے طور پر ہر سال منانے کا سلسلہ قائم ہوا جو بھارت میں تو معمولی انداز میں منایا جاتا ہے اور یہاں بڑی دھوم دھام سے پتنگ بازی اور دیگر ہر قسم کی لغویات اور بے ہودگی کا مظاہرہ کئی کئی دن تک شب وروز کیا جاتا ہے جس میں ہمارے ذرائع ابلاغ بھرپور رنگینی اور فحاشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔
حقیقت رائے کی یہ مڑھی کوٹ خواجہ سعید (کھوجے شاہ / گھوڑے شاہ) لاہور میں ہے۔ اب یہ جگہ باغبان پورہ میں باوے دی مڑھی کے نام سے مشہور ہے اور اسی علاقہ کے قبرستان میں موجود ہے۔ ہندو سکھ زائرین بسنت کے موقع پر اب تک باوے دی مڑھی پر حاضری دیتے اور منتیں مانتے ہیں۔ شاید ان میں بسنت منانے والے مسلمان بھی ہوں۔ اس لیے بسنت موسمی تہوار نہیں ہے بلکہ ہندو اسے یادگار حقیقت رائے کے طور پرمناتے ہیں اور یہ خالصتا ہندوانہ تہوار ہے لیکن مسلمانوں کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ ایک گستاخ رسول کی یاد میں منائے جانے والے تہوار پر لاکھوں روپیہ لٹا کر اور جانی نقصان اٹھا کر وہ ہر سال اس منحوس رسم کی آبیاری کرتے ہیں۔
مارچ ۲۰۰۱ء
امریکہ کا خدا بیزار سسٹم
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
روزنامہ جنگ لاہور ۲۶ فروری ۲۰۰۱ء کی ایک خبر کے مطابق امریکی ریاست ورجینیا میں سینٹ کے ریاستی ارکان نے ایک یادگاری سکہ پر ’’ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں‘‘ کے الفاظ کندہ کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں امریکہ کے قدیم باشندوں ’’ریڈ انڈین‘‘ کے اعزاز اور توقیر کے لیے ایک سلور ڈالر جاری کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس پر جنگلی بھینس کی تصویر کے ساتھ IN GOD WE TRUST (ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں) کے الفاظ کندہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ چاندی کا یہ یادگاری سکہ سکولوں میں بھی آویزاں کرنے کی تجویز ہے مگر ریاستی سینٹ کے ارکان نے سرکاری سکولوں میں یہ ماٹو آویزاں کرنے کے مسودہ قانون کو رد کر دیا ہے۔ خبرنگار کے تبصرہ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح امریکہ میں ریاست اور کلیسا کی علیحدگی کے آئینی تصور نے خدا کی ذات کو بھی متنازعہ بنا دیا ہے۔
امریکہ کے آئین میں خدا، بائبل، کلیسا اور مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ قرار دے کر ریاستی معاملات میں ان کے کسی قسم کے تعلق یا مداخلت کی نفی کی گئی ہے اور اسی بنیاد پر کسی بھی ریاستی، قانونی یا اجتماعی معاملہ کے حوالے سے مذاہب کے ذکر کو وہاں پسند نہیں کیا جاتا بلکہ قانونی طور پر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ اجتماعی معاملات میں خدا، بائبل، کلیسا اور مذہب کی دخل اندازی سے شہریوں کی آزادی رائے، خود مختاری اور اپنے فیصلے خود کرنے کا حق مجروح ہوتا ہے اس لیے مذہب اور اس کے متعلقات کو فرد کے ذاتی معاملات تک محدود رکھا جائے، ریاستی اور اجتماعی امور کے تعین پر صرف اور صرف سوسائٹی کا اختیار باقی رہنے دیاجائے اور سوسائٹی کی اکثریت کسی بھی معاملہ میں جو فیصلہ کر دے، اسے حرف آخر تصور کیا جائے۔ اسی فلسفہ اور تصور کا نام سیکولر ازم ہے اور یہ فلسفہ نہ صرف دنیا کی اکثر حکومتوں کے دساتیر کی بنیاد ہے بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے قواعد وضوابط اور فیصلوں کی پشت پر بھی اسی فلسفہ اور تصور کی کارفرمائی ہے۔
ہمارے ہاں عام طور پر ’’سیکولر ازم‘‘ کو ’’غیر فرقہ وارانہ حکومت‘‘ کے معنی میں پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیکولر ازم کی بنیاد مذہب کی نفی پر نہیں بلکہ اس سے مراد کسی ایک فرقہ پر دوسرے فرقہ کی بالادستی کو روکنا ہے اس لیے اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ محض ایک فریب کاری ہے اور اس کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ جس فلسفہ اور نظام میں خدا کے نام اور اس پر بھروسہ کے الفاظ کو محض علامتی طور پر کسی ماٹو میں بھی قبول کرنے کی گنجائش نہ ہو ، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مذہب یا اس کی کسی بنیاد کی نفی نہیں کرتا، بلکہ صرف رواداری کی تلقین کرتا ہے، خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اس مسئلہ کو ایک اور زاویہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ، سیکولر ممالک اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی طرف سے اجتماعی نظام اور دستور وقانون کے حوالے سے مسلم ممالک سے جو تقاضے کیے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے جو ایجنڈا اب تک پیش کیا گیا ہے، اس میں صرف فرقہ وارانہ رواداری کے معاملات شامل نہیں ہیں بلکہ ریاستی نظام کو مذہب اور مذہبی اقدار سے کلیتا لا تعلق کردینے کے مطالبات بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہیں اور پارلیمنٹ کے غیر مشروط اختیارات اور قانون سازی میں عوامی نمائندوں کو فائنل اتھارٹی قرار دینے کا تصور ریاستی نظم سے مذہب کو بے دخل کر دینے ہی کا دوسرا رخ ہے۔
مذکورہ خبر میں ’’ریڈ انڈین‘‘ کا بھی تذکرہ ہے جن کی توقیر اور اعزاز کے لیے یہ یادگاری سکہ جاری کیا جا رہا ہے۔ ’’ریڈ انڈین‘‘ امریکہ کے اصل اور قدیمی باشندے ہیں۔ جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو امریکہ بالکل غیر آباد براعظم نہیں تھا بلکہ وہاں پہلے سے انسان آباد تھے حتی کہ اب یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ عرب اور مسلمان کولمبس سے بہت پہلے امریکہ پہنچ چکے تھے لیکن اسی دور میں اندلس کی اسلامی ریاست کے خاتمہ اور صلیبی قوتوں کے تسلط کے باعث امریکہ میں بھی مسلمانوں کے بجائے عیسائی یورپیوں نے قبضہ جما لیا اور پھر امریکہ یورپی آباد کاروں ہی کا ملک بن کر رہ گیا حتی کہ امریکہ کی اصل آبادی کو بھی ان یورپیوں نے ’’ریڈ انڈین‘‘ کا نام دے کر اچھوت بنا دیا اور رفتہ رفتہ پورے نظام سے بے دخل کر دیا۔ ’’ریڈ انڈین’’ آج بھی امریکہ میں موجود ہیں لیکن امریکی نظام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں اور انہیں ان کے جائز حقوق دینے کے بجائے ان کے اعزاز وتوقیر کے لیے ’’یادگاری سکے‘‘ جاری کر کے انہیں بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
بہرحال یہ امریکہ کے ’’خدا بیزار سسٹم‘‘ کی ایک جھلک ہے جسے بین الاقوامی فلسفہ اور ورلڈ سسٹم کے نام پر پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن قرآن وسنت کی ابدی اور آفاقی تعلیمات پر یقین رکھنے والے مسلمانوں اور اہل دین کے ہوتے ہوئے یہ خواب کبھی تعبیر کی منزل حاصل نہیں کر سکے گا۔
علم کا مقام اور اہل علم کی ذمہ داریاں
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
(اکتوبر ۱۹۸۱ء میں کشمیر یونیورسٹی سری نگر نے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی قدس اللہ سر ہ العزیز کو ’’ڈاکٹر آف لٹریسی‘‘ کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ اس موقع پر منعقد ہونے والے کانووکیشن سے حضرت مولانا ندوی رحمہ اللہ تعالی نے جو فکر انگیز خطاب فرمایا، وہ اہل علم کے استفادہ کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ)
جناب چانسلر صاحب (بی کے نہرو، گورنر کشمیر)، پرو چانسلر صاحب (شیخ محمد عبد اللہ، چیف منسٹر کشمیر)، وائس چانسلر صاحب (ڈاکٹر وحید الدین ملک) ،اساتذۂ جامعہ، فضلاء کرام اور معزز حاضرین!
میرا عقیدہ ہے کہ علم ایک اکائی ہے جو بٹ نہیں سکتی۔ اس کو قدیم وجدید، مشرقی ومغربی، نظری وعملی میں تقسیم کرنا صحیح نہیں اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے
دلیل کم نظری قصہء جدید وقدیم
میں علم کو ایک صداقت مانتا ہوں جو خدا کی وہ دین ہے جو کسی ملک وقوم کی ملک نہیں اور نہ ہونی چاہئے۔ مجھے علم کی کثرت میں بھی وحدت نظر آتی ہے۔ وہ وحدت سچائی ہے، سچ کی تلاش ہے، علمی ذوق ہے، اور اس کو پانے کی خوشی ہے۔ اس کے باوجود میں جناب چانسلر صاحب، وائس چانسلر صاحب اور اس جامعہ کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک علمی اعزاز کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کا انتساب اور تعلق قدیم طرز تعلیم سے ہے۔
میں علم، ادب، شاعری، فلسفہ ،حکمت کسی میں اس اصول کا قائل نہیں ہوں کہ جو اس کی وردی پہن کر آئے، وہی عالم اور دانش ور ہے اور یہ مان لیا گیا ہے کہ جس کے جسم پر وردی نہ ہو، وہ نہ مستحق خطاب ہے نہ لائق سماعت۔ بد قسمتی سے ادب وشاعری میں بھی یہی حال ہے۔ جو ادب کی دکان نہ لگائے، اور اس پر ادب کا سائن بورڈ آویزاں نہ کرے، اور ادب کی وردی پہن کر ادبی محفل میں نہ آئے، وہ ’’بے ادب‘‘ ہے۔ لوگوں نے ان پیدائشی ادیبوں اور شاعروں کا قصور کبھی معاف نہیں کیا جن کے جسم پر وہ وردی دکھائی نہ دیتی ہو یا جن کو بد قسمتی سے ان وردیوں میں سے کوئی وردی نہ مل سکی ہو۔ میں علم کی آفاقیت اور علم کی تازگی کا قائل ہوں، جس میں خدا کی رہنمائی ہر دور میں شامل رہی ہے۔ اگر خلوص ہے اور سچی طلب ہے تو خدا کی طرف سے کسی وقت فیضان میں کمی نہیں۔
حضرات !
اس موقر دانش گاہ کے جلسہ تقسیم اسناد میں جو فلک بوس ہمالیہ کی ایک سرسبز وحسین وادی میں منعقد ہو رہا ہے، مجھے بے اختیار وہ واقعہ یاد آتا ہے جو عرب کے ایک خشک علاقہ میں ایک پہاڑ پر جو نہ بلند تھا اور نہ سرسبز،تقریبا چودہ سو سال پہلے پیش آیا تھا اور جس نے تاریخ انسانی ہی نہیں بلکہ تقدیر انسانی پر ایسا گہرا اور لازوال اثر ڈالا ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی اور جس کا اس ’’لوح وقلم‘‘ سے خاص تعلق ہے جس پر علم وتہذیب اور تحقیق وتصنیف کی اساس ہے اور جس کے بغیر نہ یہ عظیم دانش گاہیں وجود میں آتیں اور نہ یہ وسیع کتب خانے جن سے دنیا کی زینت اور زندگی کی قدر وقیمت ہے۔میری مراد پہلی وحی کے واقعہ سے ہے جو ۱۲ فروری ۶۱۱ء کے لگ بھگ نبی عربی محمد ﷺ پر مکہ کے قریب غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے الفاظ یہ تھے:
اقرا باسم ربک الذی خلق ۔ خلق الانسان من خلق ۔ اقرا وربک الاکرم ۔ الذی علم بالقلم ۔ علم الانسان ما لم یعلم(سورہ علق، ۱ تا ۵)
(اے محمد) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا ۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔
خالق کائنات نے اپنی وحی کی اس پہلی قسط اور باران رحمت کے اس پہلے چھینٹے میں بھی اس حقیقت کے اعلان کو موخر وملتوی نہیں فرمایا کہ علم کی قسمت سے وابستہ ہے غار حرا کی اس تنہائی میں جہاں ایک نبی امی اللہ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے پیغام لینے گیا تھا اور جس کا یہ حال تھا کہ اس نے قلم کو حرکت دینا خود بھی نہیں سیکھا تھا، جو قلم کے فن سے یکسر واقف نہ تھا۔ کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر کہیں مل سکتی ہے؟ اور اس بلندی کا تصور بھی ہو سکتا ہے کہ اس نبی امی پر ایک امت امی اور ایک ناخواندہ ملک کے درمیان (جہاں جامعات اور دانش گاہیں تو بڑی چیز ہیں، حرف شناسی بھی عام نہیں تھی) پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے اور آسمان وزمین کا رابطہ صدیوں بعد قائم ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا سے۔ جو خود پڑھا ہوا نہیں تھا، اس پر جو وحی نازل ہوتی ہے، اس میں اس کو خطاب کیا جاتا ہے کہ پڑھو۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ آپ کو جو امت دی جانے والی ہے، وہ امت صرف طالب علم ہی نہ ہوگی بلکہ معلم عالم اور علم آموز ہوگی۔ وہ علم کی اس دنیا میں اشاعت کرنے والی ہوگی۔ جو دور آپ کے حصے میں آیا ہے، وہ دور امیت کا نہیں ہوگا، وہ دور وحشت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور جہالت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا ،وہ دور علم کا دور ہوگا، عقل کا دور ہوگا، حکمت کا دور ہوگا، تعمیر کا دور ہوگا، انسان دوستی کا دور ہوگا، وہ دور ترقی کا دور ہوگا۔
باسم ربک الذی خلق (اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا) بڑی غلطی یہ تھی کہ علم کا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا تھا اس لیے علم سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے رشتہ کو یہاں جوڑا گیا۔ جب علم کو یاد کیا گیا، اس کو یہ عزت بخشی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی آگاہی دی گئی کہ اس علم کی ابتدا اسم رب سے ہونی چاہئے اس لیے کہ علم اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اسکی رہنمائی میں یہ متوازن ترقی کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلاب آفریں، انقلاب انگیز اور صاعقہ آسا آواز تھی جو ہماری دنیا کے کانوں نے سنی تھی، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر دنیا کے ادیبوں اور دانش وروں کو دعوت دی جاتی کہ آپ لوگ قیاس کیجئے کہ جو وحی نازل ہونے والی ہے، اس کی ابتدا کس چیز سے ہوگی؟ اس میں کس چیز کو اولیت دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی جو اس امی قوم اور اس کے مزاج اور دماغ سے واقف تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اقرا کے لفظ سے شروع ہوگی۔
یہ ایک انقلاب انگیز دعوت تھی کہ علم کا سفر خدائے حکیم وعلیم کی رہنمائی میں شروع کیا جا نا چاہئے اس لیے کہ یہ سفر بہت طویل، پر پیچ اور بہت پر خطر ہے ۔ یہاں دن دہاڑے قافلے لٹتے ہیں، قدم قدم پر مہیب وعمیق گھاٹیاں ہیں، گہرے دریا ہیں، قدم قدم پر سانپ اور بچھو ہیں، اس لیے اس میں ایک رہبر کامل کی رفاقت ہونی چاہئے اور وہ رہبر کامل حقیقتا خدا کی ذات ہے۔ مجرد علم وادب نہیں، وہ علم مقصود نہیں جو بیل بوٹے بنانے کا نام ہے، جو محض کھلنوں سے کھیلنے کا نام ہے۔وہ علم نہیں جو محض دل بہلانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو ایک کو دوسرے سے لڑانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو قوموں کو قوموں سے ٹکرانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو اپنے معدہ کی خندق کو بھرنے کا ذریعہ سکھانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جوزبان کو صرف استعمال کرنا سکھاتا ہے، بلکہ اقرا باسم ربک الذی خلق ۔ خلق الانسان من علق ۔ اقرا وربک الاکرم ۔ الذی علم بالقلم ۔ علم الانسان ما لم یعلم ’’پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔‘‘ وہ تمہاری ضرورتوں سے، تمہاری کمزوریوں ے کیسے ناآشنا ہو سکتا ہے؟ اقرا وربک الاکرم ۔ الذی علم بالقلم آپ خیال کیجئے کہ قلم کا رتبہ اس سے زیادہ کس نے بڑھایا ہوگا کہ اس غار حرا کی پہلی وحی نے بھی قلم کو فراموش نہیں کیا۔ وہ قلم جو شاید ڈھونڈنے سے بھی مکہ کیکسی گھر میں نہ ملتا۔ اگر آپ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو شاید معلوم نہیں کسی ورقہ بن نوفل کے یا کسی کاتب کے جو دیار عجم سے کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ کر آیا ہو، گھر میں ملتا۔
اور پھر ایک بہت بڑی انقلاب انگیز اور لافانی حقیقت بیان کی کہ علم کی کوئی انتہا نہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم ۔انسان کو سکھایا جس کا اس کو پہلے سے علم نہ تھا۔ سائنس کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ انسان چاند پر جا رہا ہے، خلا کو ہم نے طے کر لیا ہے، دنیا کی طنابیں کھینچ لی ہیں، یہ سب علم الانسان ما لم یعلم کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے؟
حضرات !
اجازت دیجئے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وادئ علم کے ایک مسافر کی حیثیت سے کچھ مشورے، کچھ تجربے پیش کروں۔
جامعات کا پہلا کام سیرت سازی ہے۔ یونیورسٹی ایسا کیرکٹر بنائے جو اپنے ضمیر کو بقول اقبال ایک کف جو کے بدلے میں بیچنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج کل کے فلسفے اور نظام یہ سمجھتے ہیں کہ اس بازار میں سب کی قیمت مقرر ہے ، کوئی اگر کم قیمت پر نہیں خریدا جا سکتا تو زیادہ قیمت پر خرید لیا جائے گا۔ ایک جامعہ کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ سیرت سازی کا کام کرے۔ وہ ایسے صاحب علم افراد پیدا کرے جو اپنے ضمیر کا سودا نہ کر سکیں، جن کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تخریبی فلسفہ، کوئی غلط دعوت وتحریک کسی دام خرید نہ سکے، جو اقبال کے الفاظ میں پورے اعتماد وافتخار کے ساتھ کہہ سکیں
کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں
غلام طغرل وسنجر نہیں میں
جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن
کسی جمشید کا ساغر نہیں میں
دوسرا فرض یہ ہے کہ ہماری جامعات سے ایسے نوجوان نکلیں جو اپنی زندگیاں حق وصداقت اور علم وہدایت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جن کو کسی کے لیے بھوکا رہنے میں وہ لذت آئے جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانے اور نائے ونوش میں آتی ہے، جن کو کھونے میں وہ مسرت حاصل ہو جو بعض اوقات کسی کو پانے میں نہیں ہوتی، جو اپنی جوانی کی بہترین توانائیاں، ذہن کی بہترین صلاحیتیں اور اپنے جامعہ کا بہترین عطیہ جس سے ان کی جھولی بھر دی گئی ہے، انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے صرف کریں۔
دانش گاہوں کو دیکھنا چاہئے کہ وہ اعلی صلاحیت کے لوگ کتنی تعداد میں پیدا کر رہی ہیں؟ میں صفائی سے کہتا ہوں کہ اب کسی ملک کی یہ تعریف نہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں یونیورسٹیاں ہیں، یہ کوتاہ نظری اب بہت پرانی ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ علم کے شوق میں، جستجو کی راہ میں، علم واخلاق کے پھیلانے اور برائیوں، بد اخلاقیوں، سفاکی ودرندگی، دولت وقوت کی پرستش کو روکنے کے لیے کتنے آدمی اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اپنی قوم کو صاحب شعور، مہذب اور باضمیر قوم بنانے کے لیے کتنی تعداد میں نوجوان موجود ہیں جو اپنی ذاتی سربلندی اور ترقی سے آنکھیں بند کر کے اس مقصد کے لیے اپنے کو وقف کرتے ہیں۔ اصل معیار یہ ہے کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دنیا کی تمام آسائشوں اور ترقیوں سے آنکھیں بند کر کے کسی گوشے میں ٹھوس علمی وتعمیری کام کر رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ادب، شاعری، فنون لطیفہ، حکمت وفلسفہ، تصنیف وتالیف سب کا مقصد یہ ہے کہ ملک وملت میں ایک نئی زندگی اور روح پیدا ہو اور وہ سراب کی نمود اور شعلہ کی بھڑک نہ ہو۔ میں اس وقت ترجمان حقیقت ڈاکٹر محمد اقبال کے یہ شعر پڑھوں گا جو انہوں نے اگرچہ کسی ادیب یا شاعر سے مخاطب ہو کر کہے تھے لیکن یہ علم وادب، فلسفہ وحکمت سب پر صادق آتے ہیں:
اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن
جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے
یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا
شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو
جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا
حضرات!
اب آخر میں مجھے اپنے ان قابل مبارک باد بھائیوں سے جو یہاں سے سند لے کے جا رہے ہیں، یا ان خوش نصیب عزیزوں سے جو ابھی اس چمن علم کی خوشہ چینی میں مصروف ہیں، کچھ کہنے کی اجازت دیجئے۔ میں اپنی بات کہنے میں (جو شاید کسی قدر خشک اور سنجیدہ ہو) ایک دلچسپ کہانی کا سہارا لوں گا، جو شاید آپ کے کانوں کا ذائقہ تبدیل کرنے میں مدد کرے۔
راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چند طلبا تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیف آور تھی اور کام کچھ نہ تھا۔ یہ نوعمر طلبا خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے۔ جاہل ملاح دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فقرہ بازی، مذاق وتفریح طبع کے لیے بے حد موزوں تھا۔ چنانچہ ایک تیز طرار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا ’’چچا میاں آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟‘‘
ملاح نے جواب دیا ’’میاں میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں‘‘
صاحبزادہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا ’’ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟‘‘
ملاح نے کہا ’’میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا‘‘
دوسرے صاحبزادہ بولے ’’جیومیٹری اور الجبرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے؟’’
ملاح نے کہا ’’حضور یہ نام میرے لیے بالکل نئے ہیں‘‘
اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا ’’مگر آپ نے جیوگرافی اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی؟’’
ملاح نے جواب دیا ’’سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟‘‘
ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے اور انہوں نے قہقہہ لگایا۔ پھر انہوں نے پوچھا ’’چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟’’ ملاح نے بتایا ’’یہی کوئی چالیس سال‘‘ لڑکوں نے کہا ’’آپ نے اپنی آدھی عمر برباد کی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں‘‘
ملاح بے چارہ خفیف سا ہو کر رہ گیا اور چپ سادھ لی۔
قدرت کا تماشا دیکھئے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا، موجیں منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھیں اور کشتی ہچکولے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کا پہلا تجربہ تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اب جاہل ملاح کی باری آئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا، بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟
لڑکے اس بھولے بھالے جاہل ملاح کا مقصد نہیں سمجھ سکے اور کالج یا مدرسہ میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنانی شروع کر دی اور جب وہ یہ بھاری بھرکم اور مرعوب کن نام گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ’’ٹھیک ہے، یہ سب تو پڑھا لیکن کیا پیراکی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟ ‘‘ لڑکوں میں کوئی پیرنا نہیں جانتا تھا، انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا ’’چچا جان یہی ایک علم ہم سے رہ گیا تھا، ہم اسے نہیں سیکھ سکے‘‘
لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا ’’میاں میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی مگر تم نے تو پوری عمر ڈبوئی اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کام نہ آئے گا، آج پیراکی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔‘‘
آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، صورت حال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے، دریا کی موجیں خونخوار نہنگوں کی طرح منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی ہیں، ساحل دور ہے او رخطرہ قریب، لیکن کشتی کے معزز ولائق سواریوں کو سب کچھ آتا ہے مگر ملاحی کا فن اور پیراکی کا علم نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے، لیکن بھلے مانسوں، شریف، خدا شناس اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا۔ اقبال نے اپنے ان اشعار میں اسی نازک صورت حال اور اس عجیب وغریب تضاد کی تصویر کھینچی ہے جس کا اس بیسویں صدی کا مہذب اور تعلیم یافتہ فرد بلکہ معاشرہ کا معاشرہ شکار ہے:
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم وپیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع وضرر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا
شریفانہ انسانی زندگی گزارنے کا بنیادی فن خدا ترسی، انسان دوستی، ضبط نفس کی ہمت وصلاحیت، ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے کی عادت، انسانیت کا احترام، انسانی جان ومال، عزت وآبرو کے تحفظ کا جذبہ، حقوق کے مطالبہ پر ادائے فرض کو ترجیح، مظلوموں اور کمزوروں کی حمایت وحفاظت اور ظالموں اور طاقت وروں سے پنجہ آزمائی کا حوصلہ، ان انسانوں سے جو دولت وجاہت کے سوا کوئی جوہر نہیں رکھتے، عدم مرعوبیت وبے خوفی، ہر موقع پر اور خود اپنی قوم ،اپنی جماعت کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کی جرات، اپنے اور پرائے کے معاملہ میں انصاف کی ترازو کی تول، کسی دانا وبینا طاقت کی نگرانی کا یقین اور اس کے سامنے جواب دہی اور حساب کا کھٹکا، یہی صحیح ،خوشگواروبے خطر اور کامیاب زندگی گزارنے کی بنیادی شرطیں اور ایک اچھے وخوش اسلوب معاشرہ اور ایک طاقتور ومحفوظ وباعزت ملک کی حقیقی ضرورتیں اور اس کے تحفظ کی ضمانتیں ہیں۔ اس کی تعلیم اور اس کے لیے مناسب ماحول مہیا کرنا دانش گاہوں کا اولین فرض اور اس کا حصول تعلیم یافتہ نسل اور ملک کے دانش وروں کی پہلی ذمہ داری ہے، اور ہم کو اس جیسے تمام مواقع پر دیکھنا چاہئے کہ اس کام کی تکمیل میں ہماری دانش گاہیں کتنی کامیاب اور ان کے سند یافتہ افراد وفضلا کتنے قابل مبارک باد ہیں اور آئندہ ان مقاصد کے حصول اور تکمیل کے لیے ہم کیا عزائم رکھتے ہیں، اور ہم نے کیا انتظامات سوچے ہیں۔
آخر میں، میں پھر آپ کی عزت افزائی، اعتماد اور جذبہ محبت واحترام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کا آپ نے اپنے اس اقدام کی شکل میں اظہار فرمایا ہے۔
شراب ۔ انسان کی بد ترین دشمن
حکیم محمود احمد ظفر
شراب انسان کی بد ترین دشمن ہے۔اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس کو حرام قرار دیا اور لوگوں کو اس سے اجتناب کا حکم فرمایا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے:
یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیھما اثم کبیر ومنافع للناس واثمھما اکبر من نفعھما۔ (البقرہ ۲۲۰)
لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدہ سے بہت زیادہ ہے۔
دنیا میں صحت کے مشہور ماہر پروفیسرہرش(HIRSCH) نے اس موضوع پر لکھی گئی اپنی کتاب میں کہا ہے:
’’شراب پر پابندی جو مہذب دنیا کا سب سے بڑا ملک امریکہ پندرہ سال تک لاگو نہ کر سکا، وہ اسلام نے گزشتہ چودہ صدیوں میں لاگو کر رکھی ہے اور اس طریقہ سے اس نے تہذیب وتمدن اور انسانیت کو بہت پہلے سے بچا رکھا ہے‘‘
قرآن حکیم میں شراب پر پابندی تین مقامات پر آئی ہے۔ ان میں سے ایک سورہ بقرہ ہے جس میں سے اوپر کی آیت نقل کی گئی ہے۔ دوسرا مقام جو شراب کی پابندی سے متعلق ہے، وہ سورۃ النساء کی آیت ۴۳ ہے اور تیسری جگہ یہ پابندی سورۃ المائدہ آیت ۹۰، ۹۱ میں بیان کی گئی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک شراب پر پابندی قرآن حکیم میں بتدریج نافذ ہوئی جب کہ بعض علما کاخیال ہے کہ یہ تینوں مقامات بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کے بیانات الگ الگ محسوس ہوتے ہیں، لیکن دراصل معنی کے نقطہ نظر سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان تینوں سورتوں میں اپنے اپنے انداز میں شراب پر پابندی ہی لگائی گئی ہے البتہ شراب سے پیدا ہونے والے خطرات اور نقصانات کو الگ الگ انداز اور طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں دس دلیلوں سے شراب کو حرام کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت جم جائے۔ چنانچہ فرمایا:
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فھل انتم منتھون۔ (المائدہ : ۹۰، ۹۱)
اے ایمان والو ! شراب، جوا، بتوں کے چڑھاوں کی جگہ اور فال نکالنے والے تیر ناپاک اور شیطانی کاموں میں سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے مابین بغض وعداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ پس کیا تم بازآنے والے ہو؟
اس آیت میں درج ذیل دس دلائل سے شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے:
۱۔ شراب کا ذکر جوئے، انصاب اور ازلام کے ساتھ کیا۔ یہ تینوں چیزیں چونکہ حرام ہیں لہذا شراب بھی حرام ہے۔
۲۔ شر اب نوشی کو رجس (ناپاک) کہا گیا اور ہر ناپاک شے حرام ہے۔
۳۔ شراب نوشی کو شیطانی کام فرمایا اور ہر شیطانی کام حرام ہے۔
۴۔ شراب نوشی سے اجتناب کا حکم فرمایا لہذا اجتناب فرض وواجب اور اس کا ارتکاب حرام ہوا۔
۵۔ آخرت ودنیا کی کامیابی اور فلاح کو شراب سے اجتناب پر منحصر کیا لہذا ارتکاب حرام ہوا۔
۶۔ شراب کو شیطان کی طرف سے عداوت کا سبب قرار دیا اور حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے۔
۷۔ شراب کی وجہ سے شیطان بغض پیدا کرتا ہے اور بغض حرام ہے۔
۸۔ شراب اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب بنتی ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنا حرام ہے۔
۹۔ شراب نماز سے روکتی ہے اور نماز سے روکنا حرام ہے۔
۱۰۔ اللہ تعالی نے انتہائی بلیغ ممانعت فرماتے ہوئے استفہاماً فرمایا ہے: ’’تو کیا تم شراب نوشی سے باز آنے والے ہو؟‘‘
سیدہ بریدہؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ اس وقت شراب پینا حلال تھا۔ اچانک میں اٹھا اور سرکار دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام عرض کیا۔ اس وقت شراب کی حرمت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے آخر میں تھا کہ ’’کیا تم باز آنے والے ہو؟‘‘ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو یہ دو آیات سنائیں۔ بعض کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا جس سے انہوں نے شراب پی لی تھی اور بعض کی شراب ابھی برتن میں موجود تھی۔ انہوں نے پیالے میں شراب زمین پر انڈیل دی اور کہنے لگے : ’’اے ہمارے رب ! ہم باز آ گئے۔ اے ہمارے رب ! ہم باز آ گئے‘‘ (تفسیر طبری ج ۷ ،ص ۴۷۔ السنن الکبری للبیہقی ج ۸، ص ۲۸۵۔ المستدرک للحاکم ج ۱، ص ۱۴۱)
اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ان تینوں سورتوں میں مختلف انداز سے شراب نوشی سے روکا گیا اور اس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ اسلام میں ہر ناپاک اور حرام شے سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔
احادیث نبویہ میں شراب کی مذمت اور وعید
اسی طرح سرکار دو عالم ﷺ نے بھی شراب کے بارے میں بڑی وعیدیں سنائی ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:
۱۔ سیدنا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا : ’’زنا کرتے وقت زانی میں ایمان کامل نہیں ہوتا اور شراب پیتے وقت شرابی میں ایمان کامل نہیں ہوتا اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان کامل نہیں ہوتا‘‘ (بخاری ج ۲، ص ۸۳۶۔ نسائی، حدیث نمبر ۵۶۷۵۔ مسلم، حدیث نمبر ۱۰۱)
۲۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ’’جس نے دنیا میں شراب پی، وہ آخرت میں (جنت کی شراب طہور) سے محروم رہے گا‘‘ (بخاری ج ۲، ص ۸۳۶)
۳۔ سیدنا عبد اللہ ابن عمرو ابن العاصؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ’’جس شخص نے شراب پی، چالیس روز تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ دبارہ شراب پیے تو اللہ تعالی پھر چالیس روز تک اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اگر وہ شراب پیے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو دوزخیوں کی پیپ پلائے۔‘‘ (نسائی، حدیث نمبر ۵۶۸۶۔ ابن ماجہ ، حدیث نمبر ۳۳۷۷)
۴۔ سیدنا عبد اللہ ابن عمرو بن العاصؓ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ’’احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ والدین کا نافرمان اور نہ شراب کا پینے والا‘‘ (نسائی ، حدیث نمبر ۵۶۸۸)
۵۔ سیدنا ابو مالک اشعریؓ فرماتے ہیں کہ سید دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ’’عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کہیں گے۔ اور عنقریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے۔ جب را ت کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر واپس لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ اس سے کہیں گے، کل آنا۔ اللہ تعالی پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا۔ اور دوسرے لوگوں یعنی زنا، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کہنے والوں کو مسخ کر کے قیامت کے روز بندر اور سور بنا دے گا‘‘ (بخاری، ج ۲، ص ۸۳۷)
۶۔ سیدنا عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ’’اللہ تعالی نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، اور شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب فروخت کرنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب کو انگوروں سے نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، اس کو لادنے والے پر اور اس پر بھی جس کے پاس لاد کر لے جائی جائے‘‘ (سنن ابی داؤد، ج ۲، ص ۱۶۱)
۷۔ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا : ’’ہر وہ شے جو عقل کو ڈھانپ لے، وہ شراب ہے اور ہر نشہ آور شے حرام ہے۔ اور جس شخص نے کسی نشہ آور شے کو پیا، اس کی چالیس روز کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی اور اگر توبہ کی تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کو طینۃ الخیال سے پلائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ طینۃ الخیال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دوزخیوں کی پیپ۔‘‘ (ابو داؤد ج ۲، ص ۱۶۲)
۸۔ عروہ بن رویم بیان کرتے ہیں کہ ابن الدیلمی سوار ہو کر سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی تلاش میں گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہا : ’’اے عبد اللہ بن عمرو، کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے شراب کے بارے میں کچھ سنا ہے؟انہوں نے فرمایا : ہاں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے جو شخص شراب پیے گا، اللہ تعالی اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا‘‘ (سنن نسائی، حدیث نمبر ۵۶۸۰۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ۳۳۷۷)
۹۔ سیدنا معاویہؓ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ’’جو شخص شراب پیے، اس کو کوڑے مارو۔ اگر وہ چوتھی دفعہ پیے تو اس کو قتل کر دو‘‘ (ترمذی ص ۲۲۸)
۱۰۔ سیدنا عثمانؓ فرماتے ہیں کہ شراب سے اجتناب کرو۔ یہ تمام گناہوں کی اصل ہے۔ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص جو نہایت عبادت گزار تھا، اس پر ایک بدکار عورت فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اپنی لونڈی بھیج کر اس کو کسی بہانے سے بلایا۔ جب وہ عبادت گزار شخص اس کے پاس پہنچا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک حسین وجمیل عورت ہے، ایک لڑکاہے اور ایک شراب کا برتن ہے۔ اس بدکار عورت نے اس سے کہا : ’’خدا کی قسم ! میں نے تم کو گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم میری خواہش نفس پوری کر و یا اس شراب کو پیو یا اس لڑکے کو قتل کر دو۔‘‘ اس عابدنے (شراب کو کم تر گناہ سمجھتے ہوئے) کہا : مجھے اس شراب سے ایک پیالہ پلا دو۔ اس عورت نے اس کو ایک پیالہ شراب پلائی۔ اس نے کہا، اور پلاؤ۔ (اسی شراب کی مدہوشی میں) پھر اس نے ا س عورت سے بد کاری کی اور اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ سو تم شراب سے اجتناب کرو کیونکہ خدا کی قسم ! شراب نوشی کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا ‘‘ (سنن نسائی، حدیث نمبر ۵۶۸۲)
ان احادیث کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں شراب نوشی پر وعید بیان کی گئی ہے، لیکن طوالت کے خوف سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔
شراب کے نقصانات
سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۱۹ میں بطور خاص شراب کی خرابیاں مادی اور روحانی پہلو سے بھی بیان کی گئی ہیں کیونکہ قرآن حکیم نے نفع کے مقابلہ میں نقصان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ اثم کا لفظ استعمال کیا جس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ اگرچہ دنیوی طور پر تم لوگوں کو اس کے کچھ فوائد نظر آئیں لیکن یاد رکھو اللہ تعالی کے ہاں شراب نوشی کا گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ دنیوی فوائد اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔لیکن اگر شراب نوشی کا سائنسی علم کے تناظر میں جائزہ لیا جائے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جن میں سے چند ایک کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔
اس سے پہلے کہ انسانی صحت پر شراب کے زہریلے اثرات کا پوری طرح سے جائزہ لیا جائے، ہمیں اس کے کیمیاوی اجزا کے متعلق تھوڑا سا ادراک حاصل کرنا چاہئے۔
علم کیمیا (Chemistry) کی رو سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ الکحل اشیا، خاص طور پر چربی کو، گلانے یا حل کرنے کے لیے ایک طاقتور محلول ہے۔ غذائی اصطلاحات میں یہ حل کرنے والی چیز نہیں بلکہ توڑ پھوڑ کے عمل پر منتج ہے۔ دوسرے لفظوں میں بنیادی خوراک یعنی شکر کو بیکٹیریا یا جراثیم کے ذریعے سے ہضم کرنے کے سلسلہ میں پیدا ہونے والی یہ ایک کیمیاوی ذیلی خوراک (Biproduct) ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر شراب انسانی جسم کے لیے ایک نقصان دہ کیمیکل تسلیم کیا گیا ہے اور انسانی جگراس کو فورا توڑ دیتا ہے یعنی اس کی زہرناکی کو ختم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس عمل کو Deoxified کہتے ہیں۔ چنانچہ شراب یا الکحل کی یقیناًکوئی غذائی اہمیت نہیں ہے جس کا دعوی اس کے رسیا اکثر وبیشتر کرتے ہیں۔ جب یہ جسم کے اندر پہنچتی ہے تو دوسری ہر قسم کی خوراک کے برعکس کنٹرول سے باہر خامروں کی تبدیلیMetabolized یا ہضم ہو جاتی ہے۔ صرف یہی ایک ظاہری فائدہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے۔ شراب یا الکحل کیا اثرات ڈالتی ہے، اس کو ذیل میں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
نظام ہضم پر شرا ب کے اثرات
شراب کا سب سے پہلا برا اثر منہ سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر منہ کے اندر ایک خاص قسم کا زندہ ماحول (Flora) ہوتا ہے جو ایک لعاب کی صورت میں ہے۔ نقصان دہ جراثیم کے لیے اس ماحول میں زندہ رہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر چونکہ شراب کی وجہ سے اس ماحول کی شدت اور قوت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے اس کا نتیجہ مسوڑھوں میں زخم (Inflection) اور سوجن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ شراب کے عادی لوگوں کے دانت نہایت تیزی سے خراب اور فرسودہ ہو جاتے ہیں۔
منہ کے بعد گلے اور خوراک کی نالی (Esophagus) کی باری آتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں۔ یہ نہایت مشکل کام سرانجام دیتے ہیں اور ان پر نہایت حساس استر (Mucous Membrane) کی تہہ ہوتی ہے۔ شراب کے اثر سے اس حساس تہہ پر برا اثر پڑتا ہے اور جلن کا باعث بنتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں اعضا کے اندر ضعف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات یہ اعضا سرطان (Cancer) کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل وہ ادارے جو سرطان جیسے موذی مرض کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، ۱۹۸۰ء کے بعد سے شراب کے خلاف دور رس اقدامات کر رہے ہیں۔
یہ بات تو ہر شخص کے علم میں ہے کہ شراب کی وجہ سے معدے کی خطرناک بیماریاں مثلا Gastritis پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ خون میں موجود لائپیڈ (Lipid) جو ایک خاص قسم کی چربی ہوتی ہے، اس کے استعمال سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ لائیپڈ ایک طرح کی حفاظتی تہہ مہیا کرتا ہے جس پر تیزابیت یعنی ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا نقصان دہ اثر نہیں ہوتا۔ اسی تہہ کی وجہ سے معدہ خود اپنے آپ کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اگرچہ فی الحال یہ پوری طرح ثابت نہیں ہوا کہ جس طرح شراب گلے اورپینے کی نالی میں سرطان کا باعث بنتی ہے، معدے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس خیال کو تقویت حاصل ہوتی جا رہی ہے کہ معدے کے کینسر میں بھی شراب کی کارستانی ہوتی ہے۔
شراب کا سب سے زیادہ نقصان دہ اثر بارہ انگشتی آنت (Dudenum) پر ہوتا ہے۔ اس جگہ نہایت نازک کیمیائی اثرات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ شراب اس کی اس خاصیت کو متاثر کرتی ہے جو مخصوص ہاضم لعاب خارج کرنے کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی کیمیائی حساسیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہاضمہ کے لیے اس اہم راستے کی تباہی کے بعد شراب جگر سے پیدا ہونے والے ہاضم لعاب (Bile) کے اخراج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تمام شرابیوں کی بارہ انگشتی آنت اور پتہ کی جھلی ہمیشہ بیماری کا شکار ہوتی ہیں یا ان کا کام اکثر صحیح نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہر شرابی کو گیس اور بد ہضمی کے ذریعہ مصیبت میں ڈالے رکھتی ہے۔ معدے کی یہ تکالیف آنتوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ نظام ہضم کے کمپیوٹر کی طرح کام کرنے والے نظام کی حسن ترتیب اور ہم آہنگی بھی تباہ وبرباد ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ایک صحت مند انسانی جسم ہر اس شے کو ہضم کر لیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، یہ نظام ہضم کو خاص قسم کی ہدایات جاری کرنے سے ہوتا ہے، مگر زیادہ اور مستقل طور پر شراب پینے والوں کے معاملہ میں یہ کنٹرول یک قلم ختم ہو جاتا ہے اور ہضم کرنے کا عمل بلا روک ٹوک اور بغیر کسی تمیز کے جاری رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس لیے کہ بے تحاشا ہضم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ خلیوں کی درمیانی جگہ (Interstices) میں چربی کا ذخیرہ کرنا شروع کر دے۔ درحقیقت چربی کی یہ کثیر مقدار دل کے پٹھوں کے نظام پر مایو کارڈک ٹیشو (Myo Cardic Tissue) پر چھا جاتی ہے اور اس طرح دل کی خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
شراب کا سب سے زیادہ خراب اثر جگر (Liver) پر ہوتا ہے۔ انسانی جگر وہ حساس لیبارٹری ہے جو شراب کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے سالمے کو زہر کی طرح محسوس کرتا ہے۔ جگر پر شراب کا اثر دو طرح سے ہوتا ہے:
۱۔ شراب خوری کی صورت میں جگر کے خلیے (Cells) الکحل ختم کرنے کی ذمہ داری میں پوری طرح مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے دوسرے کاموں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔
۲۔ جگر کے کیمیاوی عمل جو ایک سے ایک بڑھ کر حساس ہوتے ہیں، شراب کے بلا روک ٹوک اثر کے تحت درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جگر کو ایک ہی عمل بار بار دہرانا پڑتا ہے اور اس طرح بے پناہ مسلسل اور بلا ضرورت محنت اور مشقت سے جگر کو کمزوری اور ضعف واقع ہو جاتا ہے۔
یہ اثرات جگر کے لیے خطرناک نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ان اثرات میں زیادہ مشہور جگر کا سکڑنا (Cyrrhosis) ہوتا ہے جو اس کا زندہ ثبوت ہوتا ہے کہ جگر کی بربادی مکمل ہو چکی ہے۔ زیادہ خطرناک ممکنات میں سے یہ بھی ہے کہ شراب کا استعمال ایک ایک کر کے جگر کے تمام فعلوں کو تباہ کر دے۔
ان فعلوں میں سے پہلا فعل وہ ہے جس میں جگر ان اجزا کو پیدا کرتا ہے جس سے خون کا عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ چونکہ جگر ان اجزا کو پیدا نہیں کر سکتا یا اس کی پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے تمام عادی شرابی اندر سے کمزور (Anaemic) ہوتے ہیں یعنی ان میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کے چہرے خون کی نالیوں کے بڑھنے یا کھلنے کی وجہ سے تندرست اور تنومند نظر آتے ہیں لیکن ان کی ہڈیوں کے گودے (Bone Marrow) تباہ ہو چکے ہوتے ہیں یعنی درحقیقت خون کی پیداوار کا عمل ختم یا بے حد کم ہو چکا ہوتا ہے۔
مزید برآں جگر کی وہ طاقت جس کی وجہ سے جسمانی تحفظ کے اعضا جیسے مختلف قسم کے گلوبلین بالخصوص امیونو گلوبلین (Immuno Globulin) بنتے ہیں، شرابیوں میں خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بیماریوں کے خلا ف مدافعت کم سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ گلوبلین لحمیات کے وہ گروہ ہوتے ہیں جو معدنی نمکیات کے ہلکے محلولوں میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ یہ خون کے سرخ خلیوں میں پائے جاتے ہیں اور حدت کو جذب کرتے ہیں۔
شراب بعض اوقات جگر کے فعل کے اچانک رک جانے کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ اس صورت میں ایک شرابی بے ہوشی کے عالم ہی میں مر جاتا ہے۔ اسے جگر کا دیوالیہ پن (Liver Bankruptcy) کہتے ہیں۔ جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصان دہ اثرات کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ اس نکتہ کو میں اس سے زیادہ شدت سے بیان نہیں کر سکتا۔
شراب کا دوران خون پر اثر
دوران خون پر شراب کا اثر دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو جگر پر اثر کے ذریعے بالواسطہ ہوتا ہے۔ دوسرا دل کی بافتوں پر، جنہیں میو کارڈک ٹیشو (Myo Cardic Tissue) کہتے ہیں، بلا واسطہ اثر کے ذریعے۔ جگر جو خون میں چربی کی مقدار کو تحلیل کرنے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے، اس میں ضعف اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں خون لے جانے والی نسیں سخت ہوجاتی ہیں جسے Arteriosclerosis کہتے ہیں۔ اس سے فشار خون یعنی بلڈ پریشر (Hypertension) کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف الکوحل کے تیزی سے جل جانے کے عمل سے خون کے بہاؤ کے مخصوص طریق میں، جسے ہم خون کے بہاؤ کی رفتار کہتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل کی تھکان واقع ہو جاتی ہے۔ مزید برآں شراب کی وجہ سے دل میں چربی کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں اور اعصابی نظام پر نقصان دہ اثرات کے ذریعہ دل کے عمل میں خلل اندازی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عادی شرابی بالآخر یا تو جگر کے فعل میں خلل (Cyrrhosis) کی وجہ سے یا ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے اپنے خاتمے کو پہنچتے ہیں۔
وہ شخص جو دل کے عارضہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے شراب کا ایک قطرہ لینا بھی ایسے ہے جیسے اسے اپنی زندگی کی کوئی پروا نہیں اور نہ اسے اپنے جسم کے کسی عضو کے نقصان کی پروا ہے۔ شراب کے رسیا کچھ لوگوں کے یہ بھی خیالات ہیں کہ تھوڑی اور مناسب مقدار میں شراب پینے سے دل کے تشنج یا دورے میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ بادی النظر میں شراب کے فوائد میں سے ایک نظر آتا ہے لیکن سائنسی طور پر اس خیال کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہے۔ اگرچہ طبی تحریروں اور کتابوں میں اس قسم کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے لیکن بد قسمتی سے بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کے برعکس سوچتے یا محسوس کرتے ہیں۔
انسانی گردے جنہیں دوران خون کے نظام کا آخری مقام سمجھا جاتا ہے، ان کو بھی شراب کے استعمال سے سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ گردے انتہائی حساس کیمیاوی جوہر کے ملاپ (Valence) کے مقام پر چھلنی کا کام دیتے ہیں لیکن شراب (الکحل) اس نازک عمل کو بھی تہ وبالا کر دیتی ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ وہ شرابیں جن میں الکحل کی مقدار کم ہوتی ہے، گردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں چنانچہ زیادہ مقدار میں Beer پینے والوں کے گردے اکثر خراب ہوتے ہیں۔
لمف والے (Lymphatic) نظام کی انسانی جسم میں بے حد اہمیت ہے۔ ا س نظام کی خون والی نالیاں شراب کے ہاتھوں ناقابل علاج نقصان اٹھاتی ہیں اس لیے کہ چربی والے نامیاتی مرکب لائیپڈ(Lipid) کا اس نظام میں ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے۔ شراب کا نقصان دہ اثر ا حیران کن حد تک اس حفاظت بہم پہنچانے والے نظام کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالی نے، جیسا کہ مختلف آیات میں فرمایا گیا ہے، اپنی خصوصی عنایات کے ذریعہ انسانی زندگی کو حفاظت کے دیگر طریقوں سے گھیرا ہوا نہ ہوتا تو ہمیں مزید صراحت سے نظر آتا کہ شراب کس قدر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
اعصابی نظام پر شراب کا اثر
شراب عصبی خلیوں کی اس باریک جھلی میں داخل ہو جاتی ہے جو نامیاتی چربی جیسے مرکب یعنی لائیپڈ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ اس طرح اس نظام کے برقی رابطہ (Electrical Communication) میں خلل اندازی کرتی ہے۔ یہ خراب اثر دو مختلف ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا اثر نشے کے اچانک حملے کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اس کا دیرپا اثر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ شراب اعصابی نظام کو روز بروز نقصان پہنچاتی ہے جس سے کئی اقسام کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں اگرچہ شروع شروع میں شراب کا خراب اثر معمولی یا غیر واضح بھی ہو ، تب بھی اس کے دیرپا خراب اثرات شروع ہی سے مرتب ہوتے رہتے ہیں چنانچہ کچھ لوگوں کے یہ دعوے کہ ’’مجھے تو شراب سے نشہ نہیں ہوتا یا مجھ پر شراب کا اثر نہیں ہوتا‘‘ محض طفل تسلی اور خود فریبی ہے۔
شراب کے برے اثرات جوانی میں اور بطور خاص بچپن میں بے حد زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طو رپر یہ نظام لعاب پیدا کر کے فاسد مادوں کو جسم سے ایک بدرد جیسے عمل سے نکالنے کا کام کرتا ہے۔ معلوم بیماریوں جیسے ہذیان (Delirium) ، کپکپی (Tremen) ، پلائینورٹس (Plyneuritis)اور کورساکوف کے مجموعہ علامات (Korsakof Syndrome) شراب کے اثرات بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کا نہایت برا اثر اعصابی نظام کے مراکز پر ناقابل علاج حد تک ہوتا ہے۔ الفاظ کا بھولنا (Amnesia) اور ہاتھوں کا رعشہ اس اعصابی نقصان کی علامات ہوتی ہیں۔
شراب جس میں چربی پگھلانے کی صلاحیت ہوتی ہے، تخلیقی خلیوں (Reproductive Cells) میں داخل ہو کر ان کو بے حد نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی عام فہم مثالوں میں نئی نسل کی ذہانت میں کمی اور ناقص بالیدگی (Dystrophy) شامل ہیں۔ بہت سے مطالعہ جات اور سروے یہ حقیقت منکشف کرتے جا رہے ہیں کہ ذہنی طور پر غبی بچوں کے والدین اکثر وبیشتر شدید قسم کی شراب نوشی کرتے تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شراب عورت کے تخم (Ovum) اور بیضۂ حیات (Egg-cell) کے خلیے کو بہت آسانی سے نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شرابی ماؤں کے بچے اکثر موروثی طور پر دماغی یا قلبی صدمے (Shock) یا جھٹکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شرابی باپ کی طرف سے ایسے واقعات کی تعداد تیس فی صد سے زیادہ تک ہوتی ہے۔
شراب کے معاشرے پر اثرات
یہ حقیقت بار بار ثابت ہو چکی ہے کہ شراب کس طرح معاشرتی تعلقات اور استحکام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شراب سے معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:
۱۔ شرابیوں میں زود رنجی یا غصے کے فوری حملے ان کو معاشرے میں لا تعداد تنازعات میں الجھائے رکھتے ہیں۔
۲۔ لا تعداد متواتر طلاقیں معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور نتیجتا" مجرمانہ ذہنیت کے حامل بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے تمام معاشرہ خطرناک حد تک متاثر ہوتا ہے۔
۳۔ مختلف قسم کے کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں پر شراب کی وجہ سے بے دلی اور کاہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کی کارکردگی اور مہارت پر برا اثر پڑتا ہے جس کا آخری نقصان معاشرے کو پہنچتا ہے۔
۴۔ شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دوسرے کی طرف غیر ہمدردی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومی تفکر، معاشرتی اتحاد اور معاشرتی مسائل کے خلاف جہاد کا جذبہ مکمل طورپر ختم ہو جاتا ہے۔
اوپر بیان کیے گئے چار قسم کے مسائل نے مغربی معاشرت والوں کو اس قدر فکر مند کر رکھا ہے کہ انہوں نے بارہا اپنی اپنی حکومتوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ اگر شراب کا استعمال اسی طرح بڑھتا رہا تو ان ملکوں میں قومی جذبہ بالکل ختم ہو جائے گا۔
قرآن حکیم نے اس مسئلہ کی بیخ کنی کر دی ہے جس کے لیے کسی معاشرے اور کسی دانش ور میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس مسئلے کو اس طرح دو ٹوک طریقہ سے حل کرتا یعنی شراب نوشی کا یہ مسئلہ ان معاشروں کی بنیادوں کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح چاٹ رہا ہے جب کہ اللہ کے حکم نے ہمارے معاشرے کو صدیوں سے اس مصیبت سے دور رکھا ہے۔
فقہ اسلامی کے مآخذ قرآن مجید کی روشنی میں
محمد عمار خان ناصر
قرآن مجید دین کا بنیادی ماخذ ہے۔ چنانچہ وہ جہاں دین کے بنیادی احکام بیان کرتا ہے، وہاں ان دوسرے مآخذ کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے جن کی مدد سے عملی زندگی کے مختلف مسائل کے حل کے لیے ایک مفصل ضابطہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فقہ اسلامی کے تمام بنیادی مآخذ کا ثبوت خود قرآن مجید سے ملتا ہے۔
فقہ اسلامی کے مآخذ دو طرح کے ہیں: نقلی اور عقلی۔ نقلی مآخذ میں قرآن کے علاوہ سنت، اجماع اور سابقہ شریعتیں شامل ہیں، جبکہ عقلی مآخذ کے تحت قیاس، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، عرف اور استصحاب حال زیر بحث آتے ہیں۔
سنت
قرآن مجید نہایت واضح طور پر سنت کو دین کا ماخذ قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری محض یہ نہیں تھی کہ آپ کتاب اللہ کو پہنچا دیں بلکہ اس کی تبیین اور اس کے احکام کی تشریح بھی آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھی۔چنانچہ ارشاد ہے:
لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیھم رسولا من انفسھم یتلوا علیھم آیاتہ ویزکیھم ویعلمھم الکتاب والحکمۃ۔
یقیناًاللہ نے مومنوں پر انہی میں ایک رسول بھیج کر بڑا احسان کیا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا، اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ (۱)
سورۂ نحل میں ہے:
وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیھم۔
اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ایک یاددہانی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی تبیین کریں۔ (۲)
قرآن مجید واشگاف انداز میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کوایمان کی بنیاد قرار دیتا اور آپ کی اتباع کو لازم قرار دیتا ہے۔ سورۂ نساء میں ارشاد ہے:
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر۔
اے ایمان والو، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے اہل حل وعقد کی اطاعت کرو۔ اگر کسی بات میں تمہارا باہم اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ (۳)
سورۃ النساء ہی میں ہے:
فلا وربک لایومنون حتی یحکموک فی ما شجر بینھم ثم لا یجدوا فی انفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
آپ کے رب کی قسم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے باہمی تنازعات میں حکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں، اس سے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ (۴)
سورۃ النور میں ہے:
فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبھم فتنۃ او یصیبھم عذاب الیم۔
تو وہ لوگ جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آن پڑے یا ایک دردناک عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ (۵)
سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے :
وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرا ان یکون لھم الخیرۃ من امرھم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔
کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کو طے کر دیں تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ (۶)
سورۃ الحشر میں فرمایا:
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نھاکم عنہ فانتھوا۔
اور رسول تمہیں جو حکم دیں، اس کو لے لو اور جس کام سے منع کریں، اس سے رک جاؤ۔ (۷)
اجماع
قرآن وسنت کے بعد اجماع فقہ اسلامی کاتیسرا ماخذ تسلیم کیا گیا ہے اور اس کے لیے قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے استدلال کیا گیا ہے:
سورۃ آل عمران میں فرمایا:
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنھون عن المنکر وتومنون باللہ۔
تم بہترین امت ہو جسے لوگوں (پر حق کی شہادت دینے) کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ (۸)
سورۃ النساء میں ارشاد ہے:
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الھدی ویتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جھنم وساء ت مصیرا۔
اور جس نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلا، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا اور اس کو جہنم میں جلائیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ (۹)
سابقہ شریعتوں کے احکام
پچھلی شریعتوں کے جن احکام کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور ان کے منسوخ ہونے پر کوئی قرینہ نہیں، وہ بھی فقہ اسلامی میں حجت تسلیم کیے گئے ہیں۔ مثلا سورۃ النساء میں فرمایا:
وکتبنا علیہم فیھا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص۔
اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کیا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ (۱۰)
بعض اہل علم نے مرتد کے لیے قتل کی سزا پر سورۂ بقرہ میں بنو اسرائیل کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالی نے سزا کے طور پر حکم دیا:
فاقتلوا انفسکم۔
تم اپنے ساتھیوں کو قتل کرو۔ (۱۱)
قیاس
فقہ اسلامی کے عقلی مآخذ میں پہلا ماخذ قیاس ہے اور اس کی حجیت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالی نے بنو نضیر کی جلا وطنی کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے:
فاعتبروا یا اولی الابصار۔
اے اہل نظر، ان کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ (۱۲)
عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حال پر اپنے حال کو قیاس کرو اور ان کاموں سے بچو جن کی پاداش میں یہود کو یہ سزا دی گئی۔
اس کے علاوہ قرآن مجید نے بعض نظائر کے ذریعے سے بھی اہل علم کو قیا س کی تعلیم دی ہے۔ سورۃ الانعام میں حرام اشیا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:
قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اھل لغیر اللہ بہ۔
تم کہہ دو کہ مجھ پر جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا دم مسفوح ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا کوئی ایسا جانورہو جسے گناہ کرتے ہوئے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ (۱۳)
اس آیت میں حصر کے ساتھ چار چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خنزیر کو ناپاک اور ما اہل لغیر اللہ کو فسق قرار دیتے ہوئے ان کی حرمت کی علت بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح مردار اور دم مسفوح کی حرمت بھی علت پر مبنی ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے سورہ مائدہ میں انہی علتوں کی بنیاد پر چند اور چیزیں بھی محرمات کی فہرست میں شامل کی ہیں:
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اھل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ۔
تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں :مردار، خون، خنزیر کا گوشت ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور، ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے،
والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔
اوپر سے نیچے گر کر یا سینگ لگنے سے مر جائے، ایسا جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، (یہ سب حرام ہیں) صرف وہ جانور حلال ہے جسے تم نے ذبح کیا ہو۔ ایسا جانور بھی حرام ہے جسے کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی کہ تم تیروں کے ذریعے سے گوشت تقسیم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ (۱۴)
یہاں علت کی بنا پر پانچ چیزوں کا الحاق میتہ کے ساتھ اور دو چیزوں کا الحاق ما اہل لغیر اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے اور آگے علت بھی بیان کی گئی ہے کہ ذلکم فسق۔ یعنی جیسے طبعی موت مرنے والا جانور شرعی طریقے سے ذبح نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اسی طرح گلا گھٹنے کی وجہ سے، گر کر، اور سینگ لگنے کی وجہ سے مرنے والے جانور بھی حرام ہیں۔ اور جیسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور اعتقادی فسق کی وجہ سے حرام ہے، اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے جسے استھانوں پر ذبح کیا گیا ہو یا مشرکانہ طریقے سے اس پر جوئے کے تیر چلائے گئے ہوں۔
مصالح مرسلہ
قرآن مجید جگہ جگہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی جو شریعت انسانوں کے لیے نازل کی ہے، اس کا مقصد انسانوں کی صلاح وفلاح اور ان کی دنیاوی واخروی بہبود ہے۔ شریعت کے تمام احکام میں عقل وفطرت پر مبنی انسانی مصالح کی رعایت کی گئی ہے۔ مصالح کا مفہوم دو لفظوں میں جلب منفعت اور دفع حرج یعنی فائدے کا حصول اور نقصان کو دور کرناہے اور قرآن مجید ان کو دین کے بنیادی اصولوں کی حیثیت سے بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔
اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ (۱۵)
سورۃ النساء میں فرمایا:
یرید اللہ ان یخفف عنکم۔
اللہ چاہتا ہے کہ تم سے سختی کو ہٹا دے۔ (۱۶)
سورۃ الحج میں فرمایا:
ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔
اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ (۱۷)
بہت سے جزوی احکام کے ذکر کے تحت بھی قرآن مجید نے ان اصولوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ لے پالک بیٹے کے حکم کے ضمن میں فرمایا:
لکی لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیاءھم اذا قضوا منھن وطرا۔
تاکہ مسلمانوں کو اپنے لے پالک بیتوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے قطع تعلق کر لیں۔ (۱۸)
تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا :
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔
اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے۔ (۱۹)
وراثت کی تقسیم کے ضمن میں فرمایا:
لا تدرون ایھم اقرب لکم نفعا۔
تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے پہلو سے تمہارے زیادہ قریب ہے (اس لیے اللہ نے یہ حصے خود متعین کر دیے ہیں) (۲۰)
کھانے پینے میں حرام اشیا کے ذکر کے بعد فرمایا:
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔
تو جو مجبور ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ خواہش نفس کے تحت اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ (۲۱)
بچے کی رضاعت کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا:
لا تضار والدۃ بولدھا ولا مولود لہ بولدہ۔
نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو (۲۲)
کفار کے ظلم کا شکار مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:
الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ (۲۳)
قصاص کے قانون کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
ولکم فی القصاص حیوۃ یا اولی الالباب۔
اے ارباب عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ (۲۴)
دس گنا دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں ٹھہرنے کے حکم کو منسوخ کرکے فرمایا:
الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔
اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی اور جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ (۲۵)
مال فے کی تقسیم کے بارے میں ہدایات دینے کے بعد فرمایا:
کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔
تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہارے مال داروں کے مابین ہی گردش کرتا رہے۔ (۲۶)
سورۃ البقرۃ میں دیت کا حکم دے کر فرمایا:
ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ۔
یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ (۲۷)
سورۃ البقرۃ میں یتیموں کے مال کو سرپرستوں کے مال میں ملا لینے کی اجازت دینے کے بعد فرمایا:
ولو شاء اللہ لاعنتکم۔
اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا (لیکن اللہ آسانی چاہتا ہے) (۲۸)
اس سے واضح ہے کہ جب شریعت کے منصوص احکام میں تمام تر انسانی مصالح ملحوظ ہیں تو غیر منصوص احکام میں بھی ان مصالح کی رعایت ملحوظ رہنی چاہئے، چنانچہ جمہور فقہا نے، جزوی اختلافات سے قطع نظر،اصولی طور پرمصالح کو فقہ اسلامی کا ایک اہم ماخذ تسلیم کیا ہے۔
سد ذرائع
سد ذرائع کا اصول درحقیقت ان مصالح ہی کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے جن کی شریعت میں رعایت کی گئی ہے۔ ا س کا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا جو کسی پہلو سے شریعت کے معین کردہ مصالح کو نقصان پہنچا سکتی یااس کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب کا باعث بن سکتی ہیں۔قرآن مجید نے اس اصول کی بھی وضاحت کی ہے اور اسے بہت سے شرعی احکام کی بنیاد کے طور پر بیان کیا ہے:
سورۂ نور میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے متعلق بعض ہدایات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:
ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔
یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو (۲۹)
اسی سلسلہ بیان میں آگے لباس کے بارے میں بعض ہدایات دے کر فرمایا:
ذلک ازکی لھم۔
یہ ان کیلیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ (۳۰)
اسی طرح سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ ﷺ کی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا:
فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔
تم نرم لہجے میں بات نہ کرو، تاکہ وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، کسی توقع میں مبتلا نہ ہو، اور بھلے طریقے سے بات کرو۔ (۳۱)
آگے ازواج مطہرات کے حوالے سے امت کو بعض آداب کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا:
ذلکم اطھر لقلوبکم وقلوبھن۔
یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ (۳۲)
اسی ضمن میں آگے چل کر مسلمان عورتوں کے لیے حجاب کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا:
ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔
یہ اس بات کے زیادہ قرین ہے کہ ان کا (آوارہ عورتوں سے) امتیاز ہو جائے اور ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ (۳۳)
اس سے واضح ہے کہ مذکورہ تمام ہدایات کا مقصد معاشرتی شرم وحیا اور خانگی پردہ داری کی حفاظت ہے جو ظاہر ہے کہ ان ہدایات کی پامالی کی صورت میں قائم نہیں رہ سکتی۔
قرآن مجید میں بعض ایسے معاملات میں بھی سد ذرائع کے تحت بعض ہدایات دی گئی ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر دین وشریعت سے نہیں بلکہ دیگرانفرادی یا اجتماعی مصلحتوں سے ہے :
سورۃ البقرۃمیں گواہی سے متعلق ہدایات کے ضمن میں ارشاد ہے:
فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتین ممن ترضون من الشھداء ان تضل احداھما فتذکر احداھما الاخری۔
اگر گواہی کے لیے دو مرد نہ مل سکیں تو پھر اپنے پسندیدہ گواہوں میں سے ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو تاکہ اگر ایک بھولے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ (۳۴)
مزید فرمایا:
ولا تسئموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذلکم اقسط عند اللہ واقوم للشھادۃ وادنی الا ترتابوا ۔
معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی باہم طے ہونے والی مدت کو لکھ لینے سے مت اکتاؤ۔ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والاہے، گواہی کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اس کے بھی زیادہ قرین ہے کہ تم کسی شک وشبہے میں مت پڑو۔ (۳۵)
سورۂ آل عمران میں کفار کے ساتھ دوستی کی حدود بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:
یایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم۔
اے ایمان والو، کفار کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور تمہارے مشقت میں پڑنے کو پسند کرتے ہیں۔ (۳۶)
سورۃ النسائمیں اہم معاملات سے متعلق اطلاعات اور خبروں کے حوالے سے درج ذیل ہدایت دی:
واذا جاء ھم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منھم لعلمہ الذین یستنبطونہ منھم۔
اور جب امن یا جنگ کی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو یہ فورا اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول یا اپنے اہل حل وعقد کے پاس لے جاتے تو ان میں سے معاملے کی گہرائی تک پہنچنے والے لوگ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ (۳۷)
اسی طرح قرآن مجید کے درج ذیل احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ سد ذرائع کے تحت بعض مباح چیزوں کو واجب کیا جا سکتا اور بعض پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے:
رسول اللہ ﷺ کی مجالس میں مسلمانوں کو اگر کسی بات کی وضاحت دریافت کرنا ہوتی تو وہ آپ ﷺ کو راعنا (یعنی ہمارا لحاظ کیجئے) کے لفظ سے مخاطب کرتے۔ یہود مدینہ شرارت اور گستاخی کے لیے اسی لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر یوں ادا کرتے راعینا (ہمارا چرواہا) چنانچہ اللہ تعالی نے یہ ہدایت نازل فرمائی کہ مسلمان راعنا کا لفظ ہی استعمال نہ کریں تاکہ یہود کو یہ خباثت کرنے کا موقع نہ مل سکے:
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔
اے اہل ایمان، تم راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ (۳۸)
رسول اللہ ﷺ کو تنگ کرنے کے لیے منافقین نے یہ روش اپنائی تھی کہ وقت بوقت رسول اللہ ﷺ کے پاس آ جاتے اور محض آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے بے مقصد باتیں کرتے رہتے۔ قرآن مجید نے ان کی اس شرارت کا سد باب کرنے کے لیے حکم دیا کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺسے مشورہ کرنا چاہیں، وہ اس سے پہلے صدقہ کر کے آئیں:
اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم نجواکم صدقۃ۔
جب تم رسول سے کوئی مشورہ کرنا چاہو تو مشورے سے پہلے صدقہ کر کے آیا کرو۔ (۳۹)
عرف
کسی معاشرے کا عرف ورواج اگر شریعت کے منصوص احکام یا اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو تو فقہ اسلامی میں وہ قانون سازی کے ایک مستقل ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے جن احکام کے ضمن میں معاشرے کے رواج کی پیروی کی ہدایت کیہے، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:
۱۔ دیت:
فمن عفی لہ من اخیہ شئی فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔
پس جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل جائے تو وہ دستور کی پیروی کرے اور اچھے طریقے سے اس کو دیت ادا کر دے۔ (۴۰)
۲۔ عورتوں کی خانگی ذمہ داریاں اور حقوق:
ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف۔
دستور کے مطابق ان کے حقوق بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ (۴۱)
۳۔ عورتوں کا نفقہ:
وعلی المولود لہ رزقھن وکسوتھن بالمعروف۔
بچے کی ماں کا نفقہ اور اس کا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے۔ (۴۲)
۴۔ اجرت رضاعت:
لا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف۔
تم پر کوئی حرج نہیں (کہ بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے) اگر تم وہ اجرت ان کو دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کی ہے۔ (۴۳)
۵۔ بیوہ عورتوں کا حق نکاح :
فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسھن بالمعروف۔
تو دستور کے مطابق وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۴۴)
۶۔ مطلقہ عورتوں کے لیے متاع:
وللمطلقات متاع بالمعروف۔
اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو۔ (۴۵)
۷۔ یتیم کے سرپرست کااس کے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کرنا:
ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف۔
جو محتاج ہے تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ (۴۶)
۸۔ عورتو ں کا مہر:
وآتوھن اجورھن بالمعروف۔
دستور کے مطابق ان کو ان کے مہر دو۔ (۴۷)
استصحاب حال
استصحاب حال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بوقت نزاع کسی خاص حالت میں موجود ہے تو اس کی اسی حالت کو درست سمجھا اور اسے اسی پر برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اس اصول کا اطلاق قذف کے مسئلے میں ملتا ہے۔ سورۂ نور میں ارشاد ہے:
والذین یرمون المحصنت ثم لم یاتوا باربعۃ شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدۃ۔
اورجو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر اس پر چار گواہ نہیں لاتے تو تم ان کو اسی (۸۰) درے لگاؤ۔ (۴۸)
یعنی چونکہ ان عورتوں کی عام شہرت پاک دامن ہونے کی ہے اور ان کے چال چلن کے بارے میں معاشرے میں کوئی شکوک وشبہات نہیں پائے جاتے، اس لیے قانون کی نظر میں وہ پاک دامن ہی شمار ہوں گی اور اگر کوئی ان پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو اس کا ثبوت اس کے ذمے ہے اور اس کے لیے اسے چار عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے، ورنہ اسے جھوٹا قرار دے کر اس پر قذف کی حد جاری کی جائے گی۔
حوالہ جات
(۱) آل عمرا ن : ۱۶۴
(۲) النحل : ۴۴
(۳) النساء : ۵۹
(۴) النساء : ۶۵
(۵) النور : ۶۳
(۶) الاحزاب : ۳۶
(۷) الحشر : ۷
(۸) آل عمران : ۱۱۰
(۹) النساء : ۱۱۵
(۱۰) المائدہ : ۴۵
(۱۱) البقرہ : ۵۴
(۱۲) الحشر : ۲
(۱۳) الانعام : ۱۴۶
(۱۴) المائدہ : ۳
(۱۵) البقرہ : ۱۸۵
(۱۶) النساء : ۲۸
(۱۷) الحج : ۷۸
(۱۸) الاحزاب : ۳۷
(۱۹) المائدہ : ۶
(۲۰) النساء : ۱۱
(۲۱) البقرہ :۱۷۳
(۲۲) البقرہ :۲۳۳
(۲۳) الانفال : ۷۳
(۲۴) البقرہ : ۱۷۹
(۲۵) الانفال : ۶۶
(۲۶) الحشر : ۷
(۲۷) البقرہ : ۱۷۸
(۲۸) البقرہ :۲۲۰
(۲۹) النور : ۲۷
(۳۰) النور :۳۰
(۳۱) الاحزاب : ۳۲
(۳۲) الاحزاب : ۵۳
(۳۳) الاحزاب : ۵۹
(۳۴) البقرہ : ۲۸۲
(۳۵) البقرہ : ۲۸۲
(۳۶) آل عمران : ۱۱۸
(۳۷) النساء : ۸۳
(۳۸) البقرہ : ۱۰۴
(۳۹) المجادلہ : ۱۲
(۴۰) البقرہ : ۱۷۸
(۴۱) البقرہ : ۲۲۸
(۴۲) البقرہ : ۲۳۳
(۴۳) البقرہ : ۲۳۳
(۴۴) البقرہ : ۲۳۴
(۴۵) البقرہ : ۲۴۱
(۴۶) النساء : ۶
(۴۷) النساء : ۲۵
(۴۸) النور : ۴
افغانستان کے داخلی حالات پر ایک نظر
ڈاکٹر سلطان بشیر محمود
(ڈاکٹر سلطان بشیر محمود (ستارۂ امتیاز) پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنس دانوں میں سے ہیں اور سائنس کے حوالے سے قرآنی علوم ومعارف کی اشاعت کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں۔ ان دنوں افغانستان کی تعمیر نو اور وہاں سرمایہ کاری کے لیے مسلم صنعت کاروں اور تاجروں کو توجہ دلانے کی مہم میں سرگرم عمل ہیں اور اس مقصد کے لیے ’’امہ تعمیر نو برائے افغانستان‘‘ کے نام سے باقاعدہ گروپ قائم کر کے مساعی کو منظم کر رہے ہیں۔ڈاکٹر صاحب نے اپنے حالیہ دورۂ افغانستان کے تاثرات ایک مضمون میں بیان کیے ہیں جو قارئین کی دلچسپی اور استفادہ کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں مزید معلومات اور راہ نمائی کے لیے ڈاکٹر صاحب موصوف سے مندرجہ ذیل ایڈریس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 60/B ناظم الدین روڈ، F - 8/4، اسلام آباد ۔ ادارہ)
میں افغانستان جانے کے لیے پہلی بار طورخم پہنچا تو سرحد کے ہماری طرف خوف وڈر اور افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس کے ہاتھوں شریف لوگ ذلیل وخوار ہو رہے تھے۔ جیسے تیسے ہم سرحد کی دوسری جانب پہنچے تو یک لخت وہاں کا منظر بدل گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کھلی فضا میں آ گئے ہوں، وہاں خوف تھا نہ ڈر، پکڑ دھکڑ تھی نہ دھول دھونس۔ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور ملحقہ افغان علاقے کی تہذیب وثقافت ایک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ہماری طرف بجلی کا بل نہیں دیتے لیکن دوسری طرف بجلی استعمال کرنے والا ہر شخص پوری ایمان داری کے ساتھ بل دیتا ہے؟ جلال آباد سے کابل جاتے ہوئے میں نے ٹریفک کے نظام کا مطالعہ کیا۔ ہر گاڑی اصول وضابطے کے مطابق چلتی ہے، اس کے باوجود کہ وہاں کی سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کے مکانات ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں لیکن ان کے دل نہیں ٹوٹے ہیں۔
آپ اسلام آباد کے کسی مقام پر گاڑی پارک کریں تو بھکاریوں کا ایک غول آپ پر جھپٹے گا۔ کابل شہر میں بھی میں نے بھکاری دیکھے لیکن ان کا انداز بڑا باوقار تھا۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ وہاں مفلس اور ضرورت مند شخص سڑک سے ہٹ کر ایک کمبل بچھا کر بیٹھا ہوگا، اس کی زبان خاموش ہوگی۔ جو کچھ کوئی خوشی سے چاہے، دے دے، وہ آپ کا دامن نہیں پکڑے گا۔
ہمارے ہاں جس قدر سگریٹ پیا جاتا ہے، اس پر ہر سال اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ افغانستان میں بھی موجودہ حکومت کے آنے سے قبل سگریٹ کا دھواں خوب اڑایا جاتا تھا لیکن امیر المومنین نے آتے ہی اعلان کیا کہ سگریٹ مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان میں اس کے پینے پر پابندی عائد ہو گئی۔ اب یہ حالت ہے کہ آپ کابل یا قندھار شہر کے گلی کوچوں میں پھر کر دیکھ لیں، آپ کو کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ حالانکہ بے روزگاری سمیت دیگر مسائل کی وجہ سے تناؤ کا پیدا ہونا فطری امر ہے اور تناؤ ختم کرنے کے لیے سگریٹ کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن انہوں نے سگریٹ کے بجائے اللہ کا سہارا لیا ہے اور اللہ کی یاد کے ذریعے اپنی پریشانی دور کرتے ہیں۔
افغانستان کی حالت زار دیکھ کر میں دل ہی دل میں کڑھتا تھا لیکن وہ مطمئن تھے۔ ایک روز میں نے اپنے افغان دوستوں سے کہا، آپ پہلے ہی کس قدر مصیبت میں تھے، اب اقوام متحدہ نے مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایک افغان نے جواب دیا اسی میں اللہ کی بہتری شامل ہوگی۔ ہم مایوس نہیں بلکہ ہمیں توقع ہے کہ ہمارا کل آج سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی نے ہمیں زرخیز ملک دیا ہے، اس کی آب وہوا اچھی ہے۔ اللہ تعالی نے بارش برسا دی تو اس قدر فصل پیدا ہوگی جس سے ہر افغانی دو وقت کی روٹی کھالے۔ اور کیا چاہئے؟ حقیقت یہ ہے کہ افغانیوں نے اپنا طرز معاشرت اس قدر سادہ کر لیا ہے کہ انہیں اپنی زندگی مشکل محسوس ہی نہیں ہوتی۔
افغان معاشرے میں مثالی اسلامی مساوات کے نمونے جابجا نظر آتے ہیں۔ ایک روز میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کابل میں محکمہ منصوبہ بندی کے دفتر میں گیا۔ متعلقہ رئیس (Director) موجود نہیں تھا۔ دفتر کے چپڑاسی نے ہمیں بٹھایا اور چائے بنا کر لایا، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اتنے میں ڈائریکٹر صاحب آ گئے، چپڑاسی نے انہیں ہمارے بارے میں بتایا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کا چپڑاسی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔
افغانستان کا ایک اہم مسئلہ غیر قانونی ہتھیاروں کی بہتات تھی۔ افغانستان کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں چند ہتھیار غیر قانونی طور پر نہ ہوں۔ یہ افغان حکومت کا کارنامہ ہے جس نے ایسے لوگوں سے ہتھیار لے لیے جو ان کو اپنا زیور اور عزت خیال کرتے ہیں۔ یہ کام اس قدر مہارت اور محبت سے کیا گیا کہ کوئی معمولی سی سختی بھی نہیں کرنی پڑی۔ میں نے سہیل فاروقی سے کابل میں پوچھا کہ یہ حیرت انگیز کارنامہ کیسے انجام دیا گیا؟ وہ ملک کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کی مہم کے انچارج تھے۔ انہوں نے کہا جیسے ہی امیر المومنین نے حکم دیا کہ تمام افراد اپنا اپنا اسلحہ جمع کرا دیں، لوگوں نے بلا توقف حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تاہم افغان دن کی روشنی میں ہتھیار دینے پر شرم محسوس کرتے تھے، اس لیے ہم نے راتوں کو مختلف آبادیوں میں ٹرک کھڑے کر دیے۔ لوگ اپنے اپنے ہتھیار اس میں لاکر پھینک دیتے اور علی الصبح حکومت کے اہل کار اس ٹرک کو لے جاتے تھے۔ اس طرح حکومت نے یہ مشکل کام بغیر کسی جبر اور سختی کے، حکمت اور دانائی سے مکمل کر لیا۔
غربت اور بے روزگاری نے افغانوں میں بے حسی اور بخل پیدا نہیں کیا جو بے خدا معاشروں کاطرۂ امتیاز ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلال آباد سے کابل جا رہا تھا۔ راستے میں نماز ظہر کے لیے ہم نے سڑک کے کنارے ایک جگہ گاڑی کھڑی کی۔ ہم وضو کے لیے پانی کی تلاش میں تھے کہ دور سے ایک نوجوان نے ہمیں دیکھا اور بھاگم بھاگ ہمارے پاس پہنچا، بڑی محبت سے سلام کیا پھر پوچھا، کیا آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ ہم نے بتایا کہ نماز کے لیے رکے ہیں۔ وہ دوبارہ گھر کی طرف بھاگا اور چند لمحے بعد ایک کمبل لے کر واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ چھوٹا بھائی تھا جس نے جگ اور گلاس اٹھا رکھے تھے۔ اس نے ہمیں پانی پلایا اور ہمارے لیے وضو کا اہتمام کیا۔ پھر کمبل بچھایا اور ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ہمیں کھانے کی پرخلوص دعوت دی جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم قبول نہیں کرسکے۔ تاہم یہ پہلا موقع تھا جب میں نے افغانوں کی محبت کا ذائقہ چکھا۔ میں نے سوچا افغان معاشرے میں غربت کے باوجود کچھ لوگ مسافروں کے لیے دیدہ ودل فرش راہ کرتے ہیں۔ لیکن سفر کے دوران یہ تجربہ ہر مقام پر ہوا۔ میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ افغانوں سے ان کی دولت بے شک چھن گئی ہے لیکن اسلام کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت بڑھ گئی ہے۔
ایک مرتبہ ہمیں ایک ضروری کام کے لیے گورنر قندھار ملا حسن خان سے ملنے کی ضرورت پڑی۔ بظاہر تو گورنر سے ملاقات جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ میرے ذہن میں پاکستانی گورنروں کا کروفر اور پروٹوکول چھایا ہوا تھا جن سے آپ ہفتوں کوشش کے باوجود نہیں مل سکتے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے سیدھے گورنر کے دفتر پہنچے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ گورنر صاحب نماز ظہر کے وقت مسجد میں ملیں گے۔ ہم مسجد میں گئے، نماز کے بعد لوگ مختلف ٹولیوں میں جمع ہو گئے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھاکہ گورنر صاحب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ سامنے والی ٹولی میں جو شخص کھڑا ہے، وہی گورنر قندھار ہے۔ میں نے غور سے دیکھا ، اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اس کی جگہ لکڑی کی ٹانگ تھی۔ وہ باریش اور خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ باری باری لوگوں کے پاس جاتا، ان کے مسائل سنتا، احکامات جاری کرتا اور آگے بڑھ جاتا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید ہمارے پاس آتے آتے وقت ختم ہو جائے گااور ہم ملاقات سے محروم رہ جائیں گے۔ میں نے اس خدشے کا اظہار اپنے مترجم سے کیا۔ اس نے پورے یقین سے کہا، وہ ضرور ہمارے پاس آئیں گے۔ جب گورنر حسن خان ہمارے پاس پہنچے تو تاخیر پر معذرت کی اور کہا کہ سب سے آخر میں آپ سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہمارے بیرونی مہمان ہیں اور میں آپ کو خاصا وقت دینا چاہتا ہوں۔ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہم نے کہا ہم قندھار میں آٹے کی مل لگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جگہ چاہئے۔ انہوں نے کہا، اچھی بات ہے۔ اس وقت دفاتر بند ہو گئے ہیں، آپ کل صبح آٹھ بجے مجھ سے ملیں۔ اگلے روز آٹھ بجے ہم وہاں پہنچے تو گورنر صاحب پہلے سے ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم نے اپنی درخواست پیش کی۔ انہوں نے دوسرے دفاتر کو ٹیلی فون کیے اور جب تک انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اس وقت تک وہ ہم پر ہی توجہ مبذول کیے رہے۔
ایک اور دفعہ ہم قندھار کے سرکاری مہمان خانے میں تھے۔ وہاں کے سرکاری مہمان خانے میں جس کا جی چاہے، قیام کر سکتا ہے۔ گورنر صاحب کا دفتر بھی مہمان خانے کے ساتھ ہی تھا۔ سردی کے دن تھے۔ جس کمرے میں ہم مقیم تھے، وہاں ہیٹر نہیں تھا۔ شام کے وقت میں نے دیکھا، گورنر ایک شخص کے ساتھ ہیٹر اٹھائے آرہے ہیں۔ انہوں نے خود کھڑے ہو کر ہیٹر لگوایا اور کہا اس وقت ہیٹر کی تنصیب اس لیے ضروری تھی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس ہیٹر کو ایک دوسری جگہ سے آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو سردی نہ لگے۔ میں نے دل میں سوچا، بے شک اسلامی حکومت کا طرۂ امتیاز یہی ہوتا ہے کہ حکمران قوم کے خادم ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت صرف سزاؤں کا نام نہیں بلکہ خدمت خلق کا نام ہے۔
افغانستان کے وزیر اعظم ملا ربانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے منکسر المزاج شخص ہیں۔ دوران گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم سے بہت توقعات ہیں، ہم ان کی توقعات پوری نہیں کر رہے جس پر ہم شرمندہ ہیں، اس لیے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کریں۔ ہم آپ کی بھی خاطر تواضع پوری طرح نہیں کر سکتے۔ اسی دوران دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ ہماری خواہش تھی کہ ا ن سے اجازت لیں کیونکہ ہم پہلے ہی ان کا خاصا وقت لے چکے تھے۔ لیکن انہوں نے کھانا کھائے بغیر جانے کی اجازت نہ دی۔ کچھ ہی دیر بعد دستر خوان بچھ گیا۔ ہم چھ سات مہمان تھے۔ دس بارہ افراد اور تھے۔ سب دستر خوان کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد افغانی روٹی اور بینگن کے سالن کی ایک ایک پلیٹ سب کے سامنے رکھ دی گئی لیکن وزیر اعظم صاحب کے سامنے پلیٹ میں تربوز کی ایک قاش رکھ دی گئی۔ کھانے کے بعد دعا وغیرہ ہوئی اور ہم اجازت لے کر واپس آ گئے۔ میں نے راستے میں مترجم سے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کھانا کیوں نہیں کھایا، صرف تربوز کے ایک ٹکڑے پر اکتفا کیا؟ اس نے کہا، آپ تو سرکاری مہمان تھے اس لیے آپ کو کھانا حکومت نے فراہم کیا۔ وزیر اعظم صاحب کا کھانا گھر سے آتا ہے۔ ان کے گھر میں سالن نہیں پکا ہوگا، ا س لیے تربوز بھیج دیا۔ یہ باتیں کتابوں میں پڑھتے تھے، میں نے افغانستان میں اس کے عملی مظاہرے دیکھے۔
ہم نے افغانستان میں آٹے کی ایک مل لگانے کا پروگرام بنایا جس کے لیے افغانستان کی وزارت صنعت سے اجازت نامہ لینا تھا۔ ہم ان خدشات اور تفکرات میں ڈوبے ہوئے متعلقہ وزیر سے ملنے گئے کہ نہ معلوم وزیر صاحب سے ملنے کی راہ میں کتنی مشکلات حائل ہوں گی لیکن جب ہم وہاں پہنچے اور مدعا بیان کیا تو ہمیں سیدھا وزیر صاحب کے پاس پہنچا دیا گیا جو شکل وصورت اور طور طریقوں سے فقیر لگتے تھے، فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دائیں بائیں اور آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ہماری باری آئی تو پوچھا، کیسے تشریف لائے ہیں؟ ہم نے درخواست آگے بڑھا دی اور وزیر صاحب نے ہماری درخواست پڑھ کر اس پر کچھ لکھ کر ایک اور سرکاری عہدیدار کو دے دی۔ اس طرح دس منٹ تک یہ درخواست وزارت کے مختلف افسروں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی دوبارہ وزیر صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے اس پر لکھا ’’متفق بمطابق اصول وقانون‘‘ اس طرح دس منٹ کے اندر اندر ہمیں مل کی تعمیر کا اجازت نامہ مل گیا۔
ایک مرتبہ میں نے آب وبرق کے وزیر مولانا احمد جان صاحب سے تباہ شدہ بجلی کے نظام کو اتنی مشکل صورت حال کے باوجود تیزی سے قابل استعمال بنانے کا راز پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مختصر مدت میں کس طرح کابل کے دو تہائی حصے اور قندھار کو بجلی فراہم کر دی اور دیگر علاقوں کو بھی بجلی کی فراہمی ہو رہی ہے۔ تباہ وبرباد گرڈ اسٹیشنوں کو آپ بڑی سرعت اور مہارت سے قابل استعمال بنا رہے ہیں، آخر آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے نظام حکومت میں وزرا کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ متعلقہ وزیر کو اپنی وزارت کے اسرار اور رموز اور اہم تکنیکی امور سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے عوام میں تعمیر وطن کا بے پناہ جوش وجذبہ ہے۔ ہم انہیں سازگا رماحول اورموقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ مجھے کابل کے نواح میں سولہ کلو میٹر دور ایک تباہ حال پاور اسٹیشن دکھانے لے گئے جس کی تعمیر ومرمت کا کام ہو رہا تھا۔ چونکہ وہاں ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی اس لیے اس پاور اسٹیشن پر کام کرنے والوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کے وزیر صاحب آ رہے ہیں لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے یہ خوش گوار حیرت ہوئی کہ وہاں ہر شخص اپنے کام میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی بے کار بیٹھا ہوا نہ تھا۔ ان کے چیف انجینئر ایک دراز ریش افغانی تھے جن کے لباس سے دھوکا ہوتا تھا کہ شاید وہ بھی مزدور ہیں۔ ان سے گفتگو ہوئی، ان کا جذبہ اور اخلاص دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔
حکومت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے ایک خصوصی وزارت تشکیل دی ہے جو لوگوں کی دینی تربیت اور اخلاقی حالت سدھارنے کا اہتمام اور کام کرتی ہے۔ طالبان کا خیال ہے کہ مادی ترقی کے لیے اخلاقی ترقی ضروری ہے۔ دل بدلیں گے تو مالی حالت بدل جائے گی۔ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی، اسے ایک انفرادی مسئلہ خیال کیا جاتا تھا حالانکہ شریعت اسے اجتماعی فرض قرار دیتی ہے۔ اب یہاں ہر شخص فرض سمجھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی کی کسی کو اجازت نہیں۔ نماز کے وقت لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ریڑھی والا اپنی ریڑھی کو جوں کا توں چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ مجال ہے ایک پیسے کا بھی نقصان ہو۔
طالبان حکومت کے آنے سے پہلے افغانستان میں عورتوں کی جان اور عزت کس قدر خطرے میں تھی، اہل مغرب اس کا احساس رکھتے تو وہ کبھی ان پر بے بنیاد الزامات نہ لگاتے۔ بادشاہت کے دور میں مغربی تہذیب وثقافت کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک قانون منظور کیا گیا اور عورتوں کو اسکرٹ پہننے پر مجبور کیا گیا۔ داؤد کی حکومت آئی تو عورت کی تذلیل کے لیے سرعام قحبہ خانے اور شراب خانے کھول دیے گئے۔ روسی آ گئے تو شراب اور بے حیائی کا سیلاب بھی ساتھ آیا۔ روسیوں کے جانے کے بعد افغانستان طوائف الملوکی کی زد میں آ گیا۔ کابل میں مختلف نسب ونسل کے ملیشیا دندناتے پھرتے تھے۔ معصوم ومظلوم عورتوں کو جبرا گھروں سے اٹھایا جانے لگا۔ لٹیروں کی دست برد سے بچنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے بھاگ کر جانیں اور عزتیں بچائیں۔ طالبان کے دور میں اب پہلی بار عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا مرتبہ ملا ہے۔ آج اس ملک میں خواتین کو اس قدر تحفظ حاصل ہے کہ کوئی بری نظر سے ان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔
طالبان کے دور حکومت پر ایک اعتراض جبری ڈاڑھی رکھوانے کا ہے لیکن اہل مغرب اس وقت خاموش تھے جب داؤد کے دور میں ڈاڑھی والوں کو بغیر کسی قصور کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک قانون کے تحت باریش مسلمان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے تھے۔ کمیونسٹ دور میں ڈاڑھی والے گردن زدنی رہے۔ اس وقت انسانی حقوق کی تنظیموں کو تکلیف نہیں ہوئی لیکن آج وہ چلا رہی ہیں۔ طالبان ڈاڑھی رکھوا رہے ہیں۔ ڈاڑھی منڈوانا ویسے بھی غیر فطری ہے اور افغان کلچر کی تو یہ پہچان ہے۔ میرے ساتھ صنعت کاروں کا ایک گروپ افغانستان میں گیا تھا، ان میں سے اکثر ڈاڑھی کے بغیر تھے لیکن ماحول سے متاثر ہو کر سب نے ڈاڑھی رکھ لی حالانکہ غیر ملکیوں پر ڈاڑھی رکھنے کی کوئی پابندی نہیں۔
دراصل مغرب نہیں چاہتا کہ دنیا کی توجہ طالبان کے اصل مسائل کی طرف مبذول ہو۔ افغانستان ایک تباہ حال ملک ہے۔ وہ دو عشروں تک جنگ کی آگ میں جلتا رہا ہے۔ اس جنگ نے افغانستان کا ہر گھر تباہ کیا ہے۔ کوئی بھی حساس شخص وہاں جا کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔یہ شور اس لیے مچایا جا رہا ہے کہ لوگ اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ طالبان سے وحشت ودہشت منسوب کی جا رہی ہے تاکہ لوگ ان سے خوف زدہ ہو جائیں۔ افغانستان دو کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ اس میں سے بیس لاکھ افراد شہید ہوئے یعنی ہر دسواں فرد راہ حق میں کام آیا۔ پچاس لاکھ زخمی ہوئے، اس طرح مجموعی طور پر ہر تیسرا شخص روسی بربریت کا براہ راست نشانہ بنا اور باقی بالواسطہ متاثر ہوئے۔ لاکھوں ایسے یتیم اور بیوائیں ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں۔ ان کی بحالی کے لیے طالبان نے ایک مستقل وزارت قائم کی ہے جو معذور بوڑھوں، بے آسرا عورتوں اور بے خانماں بچوں کے آنسو پونچھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچاس لاکھ سے زیادہ افغان بے روزگار ہیں۔ میں نے کابل اور قندھار کے صنعتی علاقوں کو دیکھا، روسی جہازوں، توپوں اور ٹینکوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا د ی ہے۔ جب صنعتیں نہیں ہوں گی تو پھر روزگار کہاں سے آئے گا؟ا ہل مغرب کی خیانت دیکھئے، ان بے روزگار لوگوں کو روزگار میں مدد دینے کے بجائے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔
اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے علما کا خاموش مظاہرہ
ادارہ
جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ اسلام آباد اور راول پنڈی کے زیر اہتمام اسلام آباد اور راول پنڈی کے سینکڑوں علماء کرام نے ۶ فروری ۲۰۰۱ء کو اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے خاموش مظاہرہ کیا اور اقوام متحدہ کے سفارتی افسران کو مندرجہ ذیل یادداشت پیش کی۔ مظاہرہ کی قیادت پاکستان شریعت کونسل پنجاب کے امیر مولانا قاری سعید الرحمن کے ہمراہ جمعیۃ اہل السنۃ کے راہ نماؤں مولانا قاری محمد نذیر فاروقی، مولانا قاضی عبد الرشید، مولانا قاری محمد زرین، مولانا ظہور احمد علوی، مولانا عبد الخالق، مولانا گوہر رحمان، مولانا حافظ محمد صدیق اور دیگر سرکردہ علماء کرام نے کی۔
جناب سیکرٹری جنرل صاحب اقوام متحدہ
جناب عالی!
پاکستان میں دینی رہنماؤں کے خلاف جاری دہشت گردی کے حوالے سے چند معروضات گوش گزار کرنے کے لیے یہ عریضہ پیش خدمت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق آپ اس سلسلہ میں ذاتی دلچسپی لے کر متاثرین کی داد رسی کریں گے۔
۱۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے اوراس میں ہر انسان کو مکمل تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی دینی، مذہبی، سیاسی اور معاشی آزادی کا حق تسلیم کیا گیا اور اس کی مکمل ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اللہ کریم کا یہ واضح حکم جو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم میں موجود ہے، یہ ہے کہ ’’دین میں کوئی جبر نہیں‘‘ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی ﷺ نے جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ میں یہودی آباد تھے۔ حضرت محمد ﷺ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو چودہ نکات پر مشتمل تھا اور میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں یہودیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ دنیا کا یہ عظیم الشان اور اعلی ترین معاہدہ آنحضرت ﷺکی سیرت کی کتابوں میں اصل الفاظ کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔
ہمارے نبی کریم ﷺ کی تعلیمات میں انسانی حقوق کی رعایت اس حد تک کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی تیز دھار آلہ مثلا چھری وغیرہ کسی کو پکڑائے تو اس کی دھار دوسرے شخص کی طرف نہ کرے بلکہ اس کا دستہ اس کو دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معمولی سی لا پروائی سے اس شخص کا ہاتھ زخمی ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیزہ یا تیز دھار والی کوئی چیز ہاتھ میں لے کرہجوم کی جگہ مثلا بازار وغیرہ میں چلے تو اس کی دھار کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑے تاکہ اس سے کسی شخص کے زخمی ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور صرف انسانوں کی بات نہیں، ہمارے دین اور ہمارے آقا ﷺ نے ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ حقوق کے حوالے سے ہمارے نبی کریم ﷺ کی یہ تعلیمات اور ارشادات آپ کی احادیث میں واضح طور پر موجود ہیں اور ہر فرد بشر ان کا مطالعہ کر کے ان سے آگاہی حاصل کر سکتاہے۔
صرف پاکستان میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں علماء کرام ،دینی مدارس کے فضلا اور مدارس سے متعلق افراد اسی تعلیم کی ترویج واشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ یہ صرف زبانی کلامی دعوے کی بات نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی بات ہے جس کو ہر ذی شعور تسلیم کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تقریبا" دنیا کے اکثر ممالک میں پاکستانی دینی مدارس کے فارغ التحصیل علما، حفاظ اور قرا موجود ہیں۔ ان کی نگرانی کر کے، ان کی باتیں سن کر، ان کے خیالات وافکار سے آگاہی حاصل کر کے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کس قسم کی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اگر بیرون دنیا میں ان کا کردار، ان کی تعلیم اورطرز تعلیم صحیح اور انسانیت کے مطابق ہے تو یہ اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ ان کا نظام تعلیم انہی مثبت خطوط کے مطابق ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چودہ پندرہ سال دہشت گردی، تخریب کاری، لڑائی بھڑائی، مارو جلاؤ اور گھیراؤ کی تعلیم حاصل کریں اور فارغ ہونے کے بعد یہ ساری تربیت بھول کر ایک شریف، امن پسند مصلح معاشرہ اور عابد وزاہد کا روپ دھار لیں اور ان کی پوری زندگی میں اس تعلیم کی جھلک تک نظر نہ آئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دینی مدارس میں کسی منفی پہلو کی تعلیم نہیں دی جاتی۔
۲۔ پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے بعض دوسرے ممالک میں دو طرز ہائے تعلیم موجود ہیں: ایک انگریزی یا عصری طرز تعلیم اور دوسرا دینی ومذہبی طرز تعلیم۔ ان دونوں طریقوں کی ہزاروں درس گاہیں موجود ہیں لیکن دونوں میں ایک واضح فرق ہے۔ عصری تعلیم کی درسگاہوں میں طلبہ کے آپس کے اختلافات، اساتذہ کے خلاف ہڑتالیں، ہم درس افراد کا قتل، سڑکیں بلاک کرنا، جلاؤ گھیراؤ، پتھراؤ، سرکاری وغیر سرکاری املاک کی تباہی، یونین سازی، افراتفری روزمرہ کا معمول ہیں لیکن دینی مدارس میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا لیکن منفی پروپیگنڈا دینی مدارس اور مذہبی رہنماؤں کے خلاف ہی کیا جاتا ہے۔
دینی مدارس پر دہشت گردی، مذہبی منافرت، قتل وغارت گری کا الزام تو بڑے زور وشور سے عائد کیا جاتا ہے لیکن آج تک کوئی ادارہ، تنظیم اس الزام کو ایک فیصد بھی ثابت نہیں کر سکی۔ حکومت پاکستان نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رپورٹ مرتب کرائی۔ مرتب کنندگان نے جب رپورٹ پیش کی تو سات جگہوں کی نشان دہی کی کہ یہاں دہشت گردی ہوئی ہے۔ جب اراکین نے دریافت کیا کہ ان سات جگہوں نے دہشت گردی کی ہے یا یہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ جگہیں دہشت گردی کا نشانہ بنی ہیں، انہوں نے کہیں دہشت گردی نہیں کی۔
دینی مدارس اور دینی رہنما اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہر مظلوم کے حامی اور ظالم کے مخالف اور انصاف کے علمبردار ہیں اور حق وصداقت کی بات کرتے ہیں۔
۳۔ پاکستان میں ایک عرصہ سے دینی مدارس، مساجد،امام بارگاہوں اور خانقاہوں کے خلاف ایک منظم سازش شروع ہے۔ مساجد، مدارس اور امام بارگاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں، نمازیوں کو شہید کیا جاتا ہے، علماء کرام کو قتل کیا جاتا ہے اور بد امنی پھیلائی جاتی ہے۔ اب تک سینکڑوں علما اور ذاکرین کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ان میں مولانا حق نواز جھنگوی، مولانا ایثار القاسمی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، صادق حسین، مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، مولانا مفتی عبد السمیع، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا محمد عبد اللہ، علامہ عارف الحسینی، علامہ مرید عباس یزدانی، مولانا حبیب الرحمن یزدانی، مولانا احسان اللہ فاروقی، مولانا احسان الہی ظہیر، جناب سید صلاح الدین، جناب حکیم سعید جیسے حضرات شامل ہیں۔ جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو برسراقتدار افراد کے لگے بندھے بیانات چھپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ، یہ بزدلانہ حرکت ہے، اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے، مجرموں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بیانات داغ دیے جاتے ہیں اور چند دنوں کے لیے مساجد اور امام بارگاہوں کے پہرے کا نظام شروع کر دیا جاتا ہے جوآہستہ آہستہ نرم کر دیا جاتا ہے اور مجرموں کو پھر کارروائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔بعض دفعہ شہید کے لواحقین کچھ لوگوں کی نشان دہی بھی کرتے ہیں، تفتیش میں مدد دیتے ہیں، دلچسپی ظاہر کرتے ہیں لیکن ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر حکومت کی طرف سے مقرر تفتیشی ٹیم متوفی کے پس ماندگان کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اب آپ خاموش ہو جائیں، اس سے آگے تفتیش نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اگر لواحقین اصرار کریں تو ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس مسئلہ کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے اغوا ہو سکتے ہیں، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے وغیرہ۔ اس طرح کی دھمکیاں دے کر ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ مولانا محمد عبد اللہ، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار وغیرہ حضرات کے کیسوں میں اسی طرح لواحقین کی زبان بند کرائی گئی ہے۔
پاکستان میں شیعہ سنی علمی اختلاف تو ضرور موجود ہے لیکن قتل وغارت گری کا اختلاف اتنے وسیع پیمانے پر موجود نہیں ہے، تاہم ہمیں اس بات کا ضرور اقرار کرنا چاہئے کہ شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے کہیں کہیں کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں لیکن ان فرقوں کے مابین باقاعدہ جنگ کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ جب شیعہ یا سنی کسی بھی فریق کے افراد دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتے ہیں تو دوسرے فریق کی طرف سے اس کی مذمت کی جاتی ہے اور متاثرہ فریق کو انصاف مہیا کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس لیے شیعہ سنی اختلاف تو موجود ہے، شیعہ سنی جنگ نہیں۔ اس کا دوسراثبوت یہ ہے کہ ایک ہی آبادی میں، اڑوس پڑوس میں شیعہ سنی اکٹھے رہتے اور کاروبار اور لین دین کرتے ہیں۔
۴۔ موجودہ حالات کے پیش نظر پاکستان کے علماء کرام آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ بین الاقوامی انسانی حقوق کے سٹیج پر اس بات کی رپورٹ طلب کریں اور حکومت پاکستان سے اس قتل وغارت گری، دہشت گردی، لوٹ مار، افراتفری کی وجہ دریافت کریں کہ بلا وجہ علماء کرام، دینی مدارس، مساجد، امام بارگاہوں کو تخریب کاری کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور ان مسلسل واقعات کا کوئی بھی مجرم آج تک کیوں کیفر کردار تک نہ پہنچایا جا سکا؟ اگر حکومت تحفظ فراہم کرنے میں ناکام یا معذور ہے تو پھر ان اداروں کو مطلع کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔
ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان معروضات پر ہمدردی سے غور کریں گے اور مناسب اقدام کریں گے۔ اگر آپ کوئی اقدام نہیں کرسکتے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اقوام متحدہ علما کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات سے باخبر ہونے کے باوجود مجرمانہ غفلت کا شکار ہے۔
پاکستان شریعت کونسل کی سرگرمیاں
ادارہ
مجلس عاملہ کا اجلاس
پاکستان شریعت کونسل کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ۱۸ فروری ۲۰۰۱ء کو جامعہ اسلامیہ کشمیر روڈراولپنڈی صدر میں امیر مرکزیہ حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں امارت اسلامی افغانستان پر سلامتی کونسل کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں سے پیدا شدہ صورت حال کا جائزہ لیا گیا اور ملک کے تمام بڑے مکاتب فکر کی جماعتوں پر مشتمل ’’افغان ڈیفنس کونسل‘‘ کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے ساتھ مکمل تعاون کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی۔
مولانا زاہد الراشدی (گوجرانوالہ)، مولانا قاری سعید الرحمن (راولپنڈی)، مولانا حامد علی رحمانی (حسن ابدال)، مولانا عبد الرشید انصاری (کراچی)، مخدوم منظور احمد تونسوی (لاہور)، مولانا میاں عصمت شاہ کا کاخیل (پشاور)، مولانا عبد العزیز محمدی (ڈیرہ اسماعیل خان)، مولانا حافظ مہر محمد (میانوالی)، مولانا قاری جمیل الرحمن اختر (لاہور)، مولانا حسین احمد قریشی (اٹک)، مولانا صلاح الدین فاروقی (ٹیکسلا)، مولانا محمد ادریس (ڈیرہ غازی خان)، مولانا اللہ وسایا قاسم (اسلام آباد) ،مولانا عبد الخالق (اسلام آباد)، ڈاکٹر حافظ احمد خان (اسلام آباد)
- اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں نفاذ اسلام کی جدوجہد اور افغانستان کی طالبان حکومت کی حمایت میں رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے رابطہ مہم کو تیز کیا جائے اور اس سلسلہ میں مختلف شہروں میں سیمینار منعقد کیے جائیں گے جن کا آغاز ۲۱ فروری کو لاہور سے ہوگا۔ اس کے بعد کراچی، راولپنڈی، پشاور اور دیگر شہروں میں سیمینار منعقد ہوں گے جبکہ ۲۹ اپریل کو گوجرانوالہ میں پاکستان شریعت کونسل کی مرکزی مجلس شوری کا اجلاس ہوگا اور اس موقع پر کارکنوں کا اجتماع بھی منعقد کیا جائے گا۔
- اجلاس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ان سفارشات کو جلد از جلد قانونی شکل دے کر ملک میں نافذ کیا جائے اور طے شدہ پروگرام کے مطابق سودی نظام کے بروقت خاتمہ کا اہتمام کیا جائے۔
- اجلاس میں تاجرحلقوں کے بارے میں حکومت کی پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایک قرارداد میں کہا گیا کہ اس پالیسی کے نتیجہ میں معاشی حالات بہتر ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں اور تاجروں کو ہراساں کرنے کی پالیسی کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں تاجر ملک چھوڑ گئے ہیں بلکہ ملک کی بے پناہ دولت بیرون ملک منتقل ہو گئی ہے۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس پالیسی پر نظر ثانی کر کے قومی تجارت کو مزید تباہی سے بچایا جائے اور قومی دولت کے مسلسل انخلا کو روکا جائے۔
- اجلاس میں جامعہ فاروقیہ کراچی کے اساتذہ اور عملہ کے دیگر افراد کے وحشیانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں مسلسل بڑھتی ہوئی فرقہ ورانہ کشیدگی اور قتل عام کے اسباب وعوامل کی نشان دہی کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور علماء کرام اور دینی کارکنوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں۔
- اجلاس میں حضرت مولانا مفتی عبد الشکور ترمذیؒ ، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمیؒ ، حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑویؒ ، حضرت مولانا محمد لقمان علی پوریؒ اور حضرت مولانا قاضی محمد انورؒ آف ایبٹ آباد کی وفات پر گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی دینی وملی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔
لاہور میں سیمینار
پاکستان شریعت کونسل کے زیر اہتمام ۲۱ فروری ۲۰۰۱ء کو بعد نماز ظہر فلیٹیز ہوٹل لاہور میں سیمینار منعقد ہوا جس کی صدارت امیر مرکزیہ حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی نے کی جبکہ پاکستان شریعت کونسل کے راہ نماؤں مولانا زاہد الراشدی، مولانا قاری جمیل الرحمن اختر، مولانا عبد الرشید انصاری ،مولانا محمد نواز بلوچ اور مولانا حافظ ذکاء الرحمن اختر کے علاوہ جمعیۃ العلماء پاکستان کے راہ نماؤں علامہ شبیر احمد ہاشمی اور قاری زوار بہادر، جمعیۃ علماء اسلام کے راہ نماؤں مولانا محمد امجد خان اور مولانا سیف الدین سیف، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے راہ نماؤں مولانا عزیز الرحمن ثانی، مجلس احرار اسلام کے راہ نما چودھری ظفر اقبال ایڈووکیٹ، جمعیۃ اتحاد العلماء پاکستان کے سربراہ مولانا عبد المالک خان، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے راہ نما مولانا عبد الرؤف فاروقی اور اور جیش محمدکے راہ نما ڈاکٹر نذیر احمد نے خطاب کیااور علماء کرام اور دینی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
مقررین نے افغانستان کی اسلامی حکومت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ طالبان حکومت کی حمایت اور پورے ملک میں ان کی معاونت وامداد کی مہم چلائی جائے گی۔
مقررین نے وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے جہادی تحریکوں کے خلاف بیانات پر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ وزیر داخلہ پاکستانی عوام کی ترجمانی کرنے کے بجائے مغرب کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سیمینار میں دنیا بھر کی تمام مسلمان حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کیا جائے اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے اسے بھرپور امداد فراہم کی جائے۔
صوبہ سرحد کے امیر اور سیکرٹری جنرل
پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا فداء الرحمن درخواستی نے پشاور کے مولانا عصمت شاہ کاکاخیل کو پاکستان شریعت کونسل صوبہ سرحد کا امیر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مولانا عبد العزیز محمدی کو صوبائی سیکرٹری جنرل مقرر کیا ہے۔ امیرمرکزیہ نے دونوں راہ نماؤں کو اختیار دیا ہے کہ وہ باہمی مشورہ سے دیگر صوبائی عہدہ داروں اور مجلس شوری کے ارکان کا تقرر کر لیں۔ صوبہ سرحد کے امیر اور سیکرٹری جنرل سے ۵۸ نشتر آباد پشاور اور مسجد امان اسلامیہ کالونی ڈیرہ اسماعیل خان کے پتہ پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
سیکرٹری جنرل کی پریس کانفرنس
پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی نے ۱۷ فروری کو ٹیکسلا میں ایک اجتماع سے خطاب کرنے کے علاوہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولانا صلاح الدین فاروقی کی رہائش گاہ پر اخبار نویسوں سے بھی پاکستان شریعت کونسل کے موقف اور پروگرام کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شریعت کونسل اقتدار کی سیاست اور انتخابی کشمکش سے الگ تھلگ رہتے ہوئے ملک میں علمی وفکری بنیاد پر نفاذ اسلام کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اس سلسلہ میں دینی حلقوں اور علمی مراکز کے درمیان باہمی رابطہ ومفاہمت کو زیادہ سے زیادہ فروغ حاصل ہو تاکہ مشترکہ جدوجہد کی فضا قائم ہو سکے۔ مولانا زاہد الراشدی نے ملک بھر کے علماء کرام اور دینی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مشن میں پاکستان شریعت کونسل کے ساتھ شریک ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی سیاسی یا دینی جماعت کے کارکن اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے بھی پاکستان شریعت کونسل میں شامل ہو سکتے ہیں۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
ماہنامہ ’’القاسم‘‘ کا مفتی کفایت اللہؒ نمبر
مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ جنوبی ایشیا کے دینی، سیاسی اور علمی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کی خدمات اس خطہ کی ملی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی علمی ودینی راہ نمائی کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کی جرات مندانہ قیادت کی اور علماء حق کی قیادت میں ممتاز اور نمایاں مقام پر سرفراز ہوئے۔ انہیں اپنے دور میں جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے مفتی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا تھا اور ان کے فتاوی ایک عرصہ تک اہل علم کی راہ نمائی کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہیں گے۔
حضرت مفتی صاحبؒ کی وفات پر ہفت روزہ ’’الجمعیۃ‘‘ دہلی نے ان کی خدمات اور حالات زندگی پر ایک ضخیم نمبر شائع کیا تھا جس میں ممتاز اصحاب قلم اور ارباب دانش نے ان کی علمی، سیاسی اور دینی جدوجہد کے مختلف گوشوں کو آشکار کیا ہے اور نئی نسل کو ان کے حوالے سے تاریخ کے ایک پورے دور سے متعارف کرایا ہے۔ جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد نوشہرہ صوبہ سرحد کے ترجمان ماہنامہ ’’القاسم‘‘ کے سرپرست اعلی مولانا عبد القیوم حقانی نے الجمعیۃ کے اس ’’مفتی اعظم نمبر‘‘ کو جدید اضافوں اور ترتیب کے ساتھ ’’القاسم‘‘ کی خصوصی اشاعت کی شکل میں پیش کیا ہے جو آج کے نوجوان علماء کرام اور دینی کارکنوں کے لیے گراں قدر تحفہ ہے اور قافلہ حق کے ہر کارکن کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔
عمدہ کتابت وطباعت اور مضبوط جلد کے ساتھ بڑے سائز کے سوا دو سو سے زائد صفحات پر مشتمل یہ ضخیم نمبر مذکورہ بالا پتہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
’’پاکستان میں اسلام کا نظام کیسے قائم ہو؟‘‘
ہمارے محترم اور فاضل دوست مولانا حافظ مہر محمد میانوالوی کا خصوصی ذوق یہ ہے کہ وہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد وافکار کی وضاحت اور ان پر کیے جانے والے اعتراضات وشبہات کے جوابات کے ساتھ اصلاح معاشرہ اور ملک میں نفاذ اسلام کی جدوجہد کے حوالہ سے بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ زیر نظر کتابچہ اس سلسلہ میں ان کے دو مضامین پر مشتمل ہے جن میں انہوں نے اسلامی نظام کی اہمیت اور خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اس کے عملی نفاذ کے سلسلہ میں حکومت کے سامنے مختلف تجاویز پیش کی ہیں۔ چھوٹے سائز کے ۶۴ صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ پاکستان شریعت کونسل ضلع میانوالی نے شائع کیا ہے اور اسے جامعہ توحید وسنت ‘ بن حافظ جی تحصیل وضلع میانوالی سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
’’ڈاڑھی ہماری‘‘
ڈاڑھی جناب نبی اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور ہمارا دینی شعار ہے جس کی اہمیت وافادیت پر بہت سے علماء کرام نے قلم اٹھایا ہے۔ مبین ٹرسٹ پوسٹ بکس ۴۷۰ اسلام آباد ۴۴۰۰۰ نے اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ کے چند مضامین کا ایک جامع انتخاب مذکورہ بالا عنوان کے تحت شائع کیا ہے۔ آرٹ پیپر پر ۴۴ صفحات پر مشتمل یہ خوبصورت کتابچہ صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اسے مندرجہ بالا پتہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
اپریل ۲۰۰۱ء
دینی مدارس کا نصاب تعلیم
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
دینی مدارس میں مروج نصاب تعلیم کو درس نظامی کا نصاب کہا جاتا ہے جو ملا نظام الدین سہالویؒ سے منسوب ہے۔ ملا نظام الدین سہالویؒ المتوفی (۱۱۶۱ھ)حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے معاصرین میں تھے۔ ان کا قدیمی تعلق ہرات (افغانستان)کے معروف بزرگ حضرت شیخ عبد اللہ انصاریؒ سے تھا۔ اس خاندان کے شیخ نظام الدینؒ نامی بزرگ نے یوپی کے قصبہ سہالی میں کسی دور میں درس وتدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پھر ان کے خاندان میں یہ سلسلہ نسل درنسل چلتا رہا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں اس خاندان کو سہالی میں معقول جاگیر دے دی تھی جس کی وجہ سے خاندانی اور تدریسی نظام کسی رکاوٹ اور دقت کے بغیر چلتا رہا حتی کہ اورنگ زیب عالمگیرؒ کے دور میں سہالی کے شیخ زادوں نے کسی تنازع کی بنیاد پر اس خاندان کے بزرگ ملا قطب الدینؒ کو شہید کر کے ان کا گھر، سامان اور کتب خانہ جلا دیا اور اس خاندان کو سہالی کا قصبہ چھوڑنا پڑا۔ سلطان اورنگ زیب عالمگیرؒ نے ۱۱۰۵ھ میں لکھنؤ میں’’فرنگی محل‘‘ کے نام کی ایک کوٹھی انہیں الاٹ کی جو ان کی تدریسی اور علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی اور علماء فرنگی محل کا وہ عظیم علمی خاندان پورے برصغیر میں متعارف ہوا جس میں ملا نظام الدین سہالویؒ ، مولانا عبد الحلیم فرنگی محلیؒ اور مولانا عبد الحئی فرنگی محلیؒ جیسے اکابر ومشاہیر کے نام بھی شامل ہیں۔
اس دور میں برصغیر میں فقہ اور معقولات کی تعلیم کا دور دورہ تھا اور فرنگی محل کے علما ان دونوں علوم میں نمایاں ا ور امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا اپنا ایک انداز تعلیم تھا اور تعلیمی نصاب بھی خود ان کا اپنا طے کردہ تھا۔ یہ نصاب تعلیم دراصل اس خاندان کے مسلسل تجربات کا نچوڑ اور حاصل تھا جسے ملا نظام الدین سہالویؒ نے مرتب شکل میں پیش کیا اور اسی وجہ سے ان سے منسوب ہو کر ’’درس نظامی‘‘ کہلایا۔ اس نصاب میں درج ذیل گیارہ علوم وفنون میں اس دور کی بہترین کتابیں شامل کی گئیں : ۱۔صرف، ۲۔ نحو، ۳۔ منطق، ۴۔ حکمت وفلسفہ، ۵۔ ریاضی، ۶۔ بلاغت، ۷۔ فقہ، ۸۔ اصول فقہ، ۹۔ علم کلام، ۱۰۔ تفسیر قرآن اور ۱۱۔ حدیث ۔
اس نصاب کے ساتھ اس خاندان کا طرز تدریس روایتی اور کتابی تھا جس میں کتاب کا متن، حاشیہ اور حاشیہ در حاشیہ سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت بڑھانے پر زور دیا جاتا تھا اور کتاب کے نفس مضمون کی بہ نسبت اس کے دیگر متعلقات وتفصیلات کی طرف استاذ اور شاگرد کی توجہ زیادہ ہوتی تھی۔ اس طرز تدریس کی افادیت یہ تھی کہ اس سے ذہن وفکر کو تعمق اور گہرائی حاصل ہوتی تھی اور مطالعہ واستنباط کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی اور پورے جنوبی ایشیا میں صدیوں سے چلے آنے والے ہزاروں دینی مدارس کی یک لخت بندش وخاتمہ کے بعد جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت حاجی عابد حسینؒ جیسے بزرگوں نے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں رضاکارانہ چندہ اور امداد باہمی کی بنیاد پر ۱۸۶۵ء میں مدرسہ عربیہ کے نام سے ایک نئی درس گاہ قائم کی تو اس میں درس نظامی کے اسی نصاب کو تعلیم وتدریس کے نئے سلسلہ کی بنیاد بنایا اور یہی سلسلہ آگے چل کر پورے جنوبی ایشیا میں آزاد دینی مدارس کے ایک وسیع نظام کا نقطہ آغاز قرار پا گیا۔ مگر دیوبند کے حضرات نے درس نظامی کے نصاب کو من وعن قبول نہیں کیا بلکہ اس میں اس وقت کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ترمیم واضافہ بھی کیا۔ ان حضرات کا علمی وفکری تعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ سے تھا اور جہاد بالاکوٹ کی ناکامی کے باعث ولی اللہی خاندان کے مسند نشین حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؒ کی حجاز مقدس کی طرف ہجرت کے بعد اس خاندان کے علمی ورثہ اور فکری مشن کے یہی حضرات وارث تھے اس لیے انہوں نے دونوں علمی سرچشموں کے درمیان سنگم اور پل کی حیثیت اختیار کر لی اور درس نظامی کے مذکورہ نصاب کے ساتھ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے علوم وفلسفہ کا جوڑ لگا کر ایک ایسا نصاب تعلیم رائج کیا جو تھوڑے بہت رد ودبدل کے ساتھ جنوبی ایشیا کے اکثر دینی مدارس میں اس وقت بھی رائج ہے اور اب تک مختلف ادوار اور مختلف حلقوں کی ترامیم اور اضافہ کے باوجود ’’درس نظامی‘‘ ہی کہلاتا ہے۔
دار العلوم دیوبند نے جب اس نصاب کو اپنایا تو اس وقت کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں دو بنیادی تبدیلیاں کیں۔ ایک یہ کہ درس نظامی کے پرانے نصاب میں حدیث کی صرف ایک کتاب، مشکوۃ شریف تھی لیکن حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی تعلیمات وارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے دیوبند کے نصاب میں صحاح ستہ یعنی بخاری ، مسلم ، ابو داؤد ، ترمذی ، ابن ماجہ اور نسائی کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ اس وقت کی اہم ضرورت تھی جسے دیوبند کے اکابر نے محسوس کرتے ہوئے نصاب کے اندر سمودیا۔ اسی طرح جہاد بالاکوٹ کے بعد جب حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؒ ہجرت کر کے حجاز مقدس چلے گئے تو ان کی جگہ دہلی کی مسند حدیث پر حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلویؒ متمکن ہوئے جن کا رجحان حنفیت سے گریزاں اس مکتب فکر کی طرف تھا جو بعد میں اہل حدیث کے نام سے موسوم ہوا۔ ظاہر ہے کہ حدیث کی تعلیم میں ان کے ہاں انہی احادیث وروایات کی ترجیح کا پہلو غالب ہونا تھا جو ان کے رجحانات سے مطابقت رکھتا تھا اس لیے یہ تاثر عام ہونے لگا کہ حدیث نبویؐ اور فقہ حنفی الگ الگ بلکہ ایک دوسرے کے مقابل علوم کا نام ہے۔ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے حدیث کی تعلیم وتدریس کے دوران فقہ حنفی کے مسائل واحکام کے احادیث نبویہؐ سے اثبات اور ان کی ترجیح کے طرز کو اپنایا جسے بعد میں حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے کمال تک پہنچا دیا۔
ان دو تبدیلیوں میں سے ایک کا تعلق نصاب میں اضافہ سے ہے اور دوسری تبدیلی طرز تدریس سے تعلق رکھتی ہے جو ظاہر ہے اس وقت کی ضروریات اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل میں لائی گئیں لیکن اس کے بعد نصاب اورطرز تعلیم پر جمود کی ایسی مہر ثبت کر دی گئی کہ زمانے کی ضروریات اور تقاضوں سے آنکھیں بند کر لینے کوہی عافیت کا واحد ذریعہ سمجھ لیا گیا حتی کہ بڑے بڑے اکابر چیختے چلاتے رہ گئے مگر مدارس دینیہ کے ارباب حل وعقد کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس سلسلہ میں ارباب مدارس کے بھی کچھ تحفظات اور مجبوریاں ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں اور ہم نے اپنے مضامین میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے لیکن ان تحفظات اور مجبوریوں کے دائرے قائم رکھتے ہوئے بھی جو ضروری ترامیم اور اضافے آسانی کے ساتھ ہو سکتے تھے، بدقسمتی سے انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا اور ابھی تک مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالی ہمارے دور کے اکابر علما میں سے تھے اور ان کا شمار حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی کے ابتدائی دور کے مایہ ناز شاگردوں میں ہوتا ہے جب حضرت شاہ صاحبؒ دار العلوم دیوبند میں پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا نعمانی اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ جس سال وہ دورۂ حدیث سے فارغ ہوئے تو حضرت شاہ صاحبؒ نے دورۂ حدیث کے طلبہ کو رخصت کرنے سے قبل ایک خصوصی نشست میں ہدایات اور نصائح سے نوازا جن میں سب سے اہم نصیحت یہ تھی کہ اگر اسلام کی دعوت وتبلیغ کا کام صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے انگریزی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ اس واقعہ کو پون صدی گزر چکی ہے مگر ہمارے مدارس اب بھی انگریزی زبان کے بارے میں تردد کا شکار ہیں کہ سرے سے اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز نے بھی اس مسئلے پر بہت کچھ فرمایا مگر ان کی آواز بھی صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ میں اس موقع پر ان کے دو تین ارشادات نقل کرنا چاہوں گا جس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ دینی مدارس کے نصاب ونظام میں تبدیلی کی ضرورت پر اکابر علما کے احساسات اور اس کے ارباب اختیار کے ذہنی وفکری جمود کے درمیان کتنا فاصلہ تھا۔
حضرت تھانویؒ قرآن کریم کی تدریس کے مروجہ طرز پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’قرآن شریف کا طرز عام مصنفین کے طرز پر نہیں ہے بلکہ محاورہ بول چال کا طرز ہے۔ نہ اس میں اصطلاحی الفاظ کی پابندی۔ ناواقف لوگ اس کو عام تصانیف کے طریقہ پر منطبق کرنا چاہتے ہیں اس لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو صاحب کشاف نے بھی لکھا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ضروری صرف ونحو اور کسی قدر ادب پڑھا کر قرآن شریف کا سادہ پڑھا دینا مناسب ہے کیونکہ کتب درسیہ کی تحصیل کے بعد دماغ میں اصطلاحات رچ جاتی ہیں پھر طالب علم قرآن شریف کو اسی طرز پر منطبق کرنے لگتا ہے۔ اس طرح قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر پھر فنون ضرور پڑھے کیونکہ بعض مقامات قرآنیہ بغیر فنون کے حل نہیں ہوتے‘‘ (کلام الحسن ص ۳۲)
اسی مسئلہ کو ایک اور انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ
’’اہل مدارس طرز تعلیم میں کچھ ترمیم کریں۔ جیسے بعض متون بغیر شرح کے پڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح جلالین سے پہلے قرآن مجید بھی بغیر کسی خاص تفسیر کے زبانی حل کے ساتھ پڑھایا جایا کرے۔ یا تو پورا قرآن پہلے پڑھا دیا جائے یا ایسا کریں کہ مثلا ربع پارہ اول خالی قرآن کریم میں پڑھا دیا جائے پھر اسی قدر جلالین پڑھا دی جائے اور مدرس اپنی سہولت کے لیے خواہ جلالین اپنے پاس رکھے یا اور کوئی مبسوط تفسیر۔ تو طلبہ کو پڑھنے میں، اسی طرح یاد کرنے کی اور مطالعہ کر کے حل کرنے کی عادت پڑ جائے گی‘‘ (اصلاح انقلاب ص ۴۷)
جبکہ نصاب میں ضروری اضافوں کے حوالے سے حضرت تھانویؒ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ:
’’یہ میری بہت پرانی رائے ہے اور اب تو رائے دینے سے بھی طبیعت افسردہ ہو گئی اس لیے کہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ رائے یہ ہے کہ تعزیرات ہند کے قوانین اور ڈاک خانہ اور ریلوے کے قواعد بھی مدارس اسلامیہ کے درس میں داخل ہونے چاہییں۔ یہ بہت پرانی رائے ہے مگر کوئی مانتا اور سنتا ہی نہیں۔‘‘ (الافاضات الیومیہ، جلد ششم، ص ۴۳۵)
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ العزیزکے ان ارشادات کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دینی مدارس کے نصاب ونظام اور طرز تدریس دونوں میں تبدیلی اور وقت کی ضروریات کو ان میں سمونے کی ضرورت کا احساس بہت پرانا ہے اور اس کا اظہار بڑے بڑے اکابر نے کیا ہے لیکن دوسری طرف مدارس کے ارباب حل وعقد کے جمود کی بھی داد دیجیے کہ حضرت تھانویؒ جیسے بزرگ کو بھی اس حسرت کے ساتھ سپر انداز ہونا پڑا ہے کہ ’’کوئی مانتا اور سنتا ہی نہیں‘‘۔
ہمارے دور میں اس مسئلہ پر سب سے زیادہ بحث حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس اللہ سرہ العزیز نے کی ہے اور درجنوں مضامین ومقالات میں انہوں نے نصاب تعلیم اور طرز تدریس میں وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ نصاب میں تین طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے:
(۱) تخفیف، یعنی بھاری بھرکم نصاب کو کچھ ہلکا کیا جائے اور ایک ہی فن میں درجنوں کتابیں الگ الگ پڑھانے کے بجائے تین چار اہم اور زیادہ مفید کتابوں کی تعلیم دی جائے۔
(۲) تیسیر، یعنی مشکل پسندی کا طریقہ ترک کر کے غیر متعلقہ مباحث میں طلبہ کے ذہنوں کو الجھانے کے بجائے نفس کتاب اور نفس مضمون کی تفہیم کو ترجیح دی جائے۔
(۳) اثبات وترمیم، یعنی غیر ضروری فنون کو حذف کر کے جدید اور مفید علوم کو شامل کیا جائے۔ حضرت بنوریؒ نے اس سلسلہ میں جن نئے علوم کو نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، ان میں ۱۔ تاریخ اسلام، ۲۔ سیرت النبیؐ، ۳۔ جدید عربی ادب وانشا، ۴۔ جدید علم کلام، ۵۔ ریاضی اور ۶۔ معاشیات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔
اس مسئلہ پر حضرت مولانا ابو الکلام آزادؒ نے بھی بحث کی ہے اور انہوں نے ۲۲ فروری ۱۹۴۷ء کو لکھنؤ میں عربی مدارس کے نصاب کے بارے میں ایک کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے نصاب ونظام پر ایک جامع اور مکمل تبصرہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس موضوع سے دل چسپی رکھنے والے ہر شخص کو اس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہئے۔ یہ خطبہ صدارت ادارہ نشریات اسلام اردو بازار لاہورکے طبع کردہ ’’خطبات آزادؒ ‘‘ میں موجود ہے اور ہم نے بھی ماہنامہ الشریعہ کے نومبر ۱۹۹۳ء کے شمارے میں اسے شائع کیا ہے۔ اس مختصر مضمون میں اس کے تمام ضروری مباحث اور پہلوؤں کا تذکرہ تو ممکن نہیں ہے مگر دو اقتباسات ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ وقت کی ضروریات اور تقاضوں سے ہماری بے خبری بلکہ بے پروائی کا کچھ اندازہ ہو سکے۔
’’حضرات ! مجھے معاف کیا جائے۔ ۱۴ تا ۱۵ برس تک لڑکے پڑھتے ہیں اور دس سطریں عربی کی صلاحیت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ اگر لکھیں گے تو ایسی عربی ہوگی جس کو ایک عرب نہ پہچان سکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقص ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا۔ ضرورت ہے کہ عربی کی تعلیم کی نیو نئے سرے سے قائم کریں۔ بہترین کتابیں موجود ہیں، بہترین مواد موجود ہے، ایسی کتابیں موجود ہیں کہ عربی ادب کے معجزات میں جن کا شمار ہو سکے۔‘‘
اسی خطبہ میں مولانا آزادؒ فرماتے ہیں
’’میں نے بھی پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر انہی کتابوں کو پڑھا ہے اور میری ابتدائی تعلیم کا وہ سرمایہ ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی میرے اندر مخالفت کا خیال نہیں پیدا ہو سکتا مگر میرا دل اس بارے میں زخمی ہے۔ یہ معاملہ تو ایسا تھا کہ آج سے ایک سو برس پہلے ہم نے اس چیز کو محسوس کیا ہوتا اور اس حقیقت کو تسلیم کیا ہوتا کہ اب دنیا کہاں سے کہاں آ گئی ہے اور اس کے بارے میں کیا تبدیلی ہمیں کرنا ہے لیکن اگر سو برس پہلے ہم نے تبدیلی نہیں کی تو کم از کم یہ تبدیلی ہم کو پچاس برس پہلے کرنا چاہئے تھی۔ لیکن آج ۱۹۴۷ء میں اپنے مدرسوں میں جن چیزوں کو ہم معقولات کے نام پر پڑھا رہے ہیں، وہ وہی چیزیں ہیں جن سے دنیا کا دماغی کارواں دو سو برس پہلے گزر چکا۔ آج ان کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔‘‘
الغرض دینی مدارس کی تمام تر خدمات، قربانیوں، ایثار اور تاریخی کردار کے باوجود آج کے دور کے تقاضوں اور ضروریات کے حوالے سے ان کے نصاب ونظام میں ضروری رد وبدل اور مناسب ترمیم واضافہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے جس کی طرف اکابر علماء حق ہر دور میں توجہ دلاتے چلے آ رہے ہیں اور ہماری گزارش بھی یہی ہے کہ وقت کے تقاضوں کو محسوس کیا جائے، دینی ضروریات کو سامنے رکھا جائے اور مستقبل کے امکانات وخطرات کا ادراک کرتے ہوئے باہمی مشاورت کے ساتھ جو تبدیلی بھی ناگزیر ہو ،اسے اختیار کرنے میں تامل سے کام نہ لیا جائے۔ اس سلسلہ میں دینی مدارس کے سینئر اساتذہ اور دور حاضر کے مسائل وضروریات پر نظر رکھنے والے ارباب علم ودانش کے درمیان وسیع پیمانے پر مذاکروں اور مباحثوں کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنجیدگی کے ساتھ سننے اور اس کی روشنی میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے ارباب مدارس اس ضرورت کا جلد احساس کریں اور اسے پورا کرنے کے لیے حوصلہ اور جرات کے ساتھ پیش رفت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین
انتہائی افسوس ناک پولیس ایکشن
مارچ ۲۰۰۱ء کے تیسرے ہفتے کے دوران میں لاہور میں ملک کے معروف روحانی پیشو ااور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر حضرت مولانا سید نفیس شاہ صاحب الحسینی مدظلہ کی رہائش گاہ پر ندوۃ العلماء لکھنؤ سے آئے ہوئے حضرت مولانا سید سلمان ندوی اور ان کے رفقا قیام پذیر تھے کہ نصف شب کو پولیس اہل کاروں نے وہاں دھاوا بول دیا، چند معزز مہمانوں سمیت مکان میں موجود متعدد حضرات کو گرفتار کر کے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر پولیس ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا اور رات بھر انہیں پریشان و ذلیل کیا گیا۔ یہ پولیس ایکشن نہایت افسوس ناک بلکہ شرمناک ہے جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہو گی۔ اس پولیس ایکشن کی جس قدر مذمت کی جائے، کم ہے۔ ہم گورنر پنجاب سے مطالبہ کرتے ہوئے کہ وہ ذاتی طور پر اس واقعہ کا نوٹس لیں اور اس کے ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف سخت کارروائی کے علاوہ ندوۃ العلما لکھنؤ سے آنے والے معزز مہمانوں کی توہین پر سرکاری سطح پر معذرت کی جائے۔
سؤر کے گوشت کے نقصانات
حکیم محمود احمد ظفر
قرآن حکیم نے سؤر کے گوشت کے بارے میں یہ حکم دیا
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اھل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ (البقرہ ۱۷۳)
بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار، خون اور سؤر کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری اور اضطرار کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھالے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی یا حد سے تجاوز کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
قرآن حکیم خنزیر کے گوشت کو چار مختلف آیات میں منع کرتا ہے۔ اس کے حرام ہونے کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۳، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۳، سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۴۵ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر ۱۱۵ میں صریحا دیا گیا ہے۔ اس حکم کو چار مختلف سورتوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو پرزور طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے اور یہ کہ ہر شخص اس مسئلہ پر پوری توجہ کرے۔
روز مرہ زندگی میں سؤر سے دور رہنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ یہ بے حد غلیظ جانور ہے اور ان میں مشہور قسم کے نقصان دہ طفیلی جراثیموں کی تھیلی Trichina Cyst پائی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے ان معاشروں میں جہاں کئی سالوں تک سؤر کے گوشت پر پابندی رہی ہے، کچھ لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جانور کے ڈاکٹری معائنے کے بعد اس کو کھایا جا سکتا ہے۔
سؤر کے گوشت کی ممانعت کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ گزشتہ ۲۵ سالوں میں قرآن حکیم کے اس حکم کی تائید میں سائنس نے متعدد وجوہ ڈھونڈلی ہیں اور خود سائنس دان بھی اللہ تعالی کے اس حکم پر حیرت زدہ رہ گئے ہیں جو اس نے قرآن حکیم کی اس آیت میں دیا ہے۔ اب میں سؤر کے جسم کے ان حصوں پر سائنسی تحقیقات کا خلاصہ پیش کروں گا جو انسانی صحت کے لیے مضرت رساں ہیں۔
مشہور جرمن میڈیکل سائنس دان ہینز ہائنرک ریکویگ (Hans Heinrich Rechweg) نے سؤر کے گوشت میں ایک عجیب قسم کی زہریلی پروٹین سٹوکسن (Sutoxin)کی نشان دہی کی ہے جس سے کئی قسم کی الرجی والی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زہر اس قسم کی الرجی والی بیماریوں مثلا ایگزیما اور دمہ کے دورے (Asthamatic Rash) کا باعث بنتی ہے۔ اگر سٹوکسن کی مقدار یا خوراک کم ہو تو بھی اس سے تھکاوٹ اور جوڑوں کے درد کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر کچھ لوگوں کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ سؤر کا گوشت سستا ہوتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں بہت مہنگی ہوتی ہیں لہذا ان بیماریوں کے علاج میں وقت کے ضیاع اور دواؤں کے اخراجات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہئے۔ تب اس گوشت کی کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی۔
جانوروں پر تجربات کے سلسلے میں سؤر کا اثر ہمیشہ نظر آجاتا ہے۔ اس جانور کے رطوبت چھوڑنے والے غدودوں کے نظام (Lymphatic System) میں تیزی سے ہونے والی فرسودگی سے ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وجہ سے ہے کہ یہ جانور نقصان دہ بیکٹیریا سے بھری ہوئی خوراک متواتر بغیر وقفہ کے کھاتا رہتا ہے۔
خنزیر کے گوشت میں ایک عنصر میوکو پولائزک چرائڈ (Muco Polysac Charides) کافی تعداد میں پایا جاتا ہے اور چونکہ اس میں گندھک (Sulphur) ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے جوڑوں کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سؤر میں بڑھنے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے والے ہارمونز ایک بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کے عادی لوگوں کے جسم بھی بدنما اور عیب زدہ ہو جاتے ہیں۔
ایک اور پریشان کن بیماری جو سؤر کے گوشت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اسے شیپ وائرس (Sheep virus) کہتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ خود سؤر کے پھیپھڑوں میں بھی یہ کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔
سؤر کا گوشت خون میں چربی والے اجزا کے تناسب کا ضرورت سے زیادہ مقدار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج کل ایسی خوراک یعنی قیمہ بھری آنتوں (Sausages) اور سلامی (Salami) وغیرہ بہت مرغوب سمجھی جاتی ہیں۔ سؤر کھانے والوں کے جسم رفتہ رفتہ ایک انگیٹھی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یورپ کے کئی شہروں میں یہ حقیقت بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ پروفیسر لیٹرے (Prof. Lettre) نے تابکاری طریقے (Radioactive Tagging)استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ خوراک جسم کے اسی حصے میں مرکوز ہو جاتی ہے جس حصہ کی وہ خوراک ہے۔ چنانچہ اس نظریہ کا ثبوت مل جاتا ہے کہ سؤر کھانے والوں کے چوتڑوں میں چربی اکٹھی ہو جاتی ہے۔
سؤر کھانے والوں کو لاحق ہونے والی ایک اور مہلک بیماری چنونے یا کیڑوں والی بیماری ہوتی ہے جسے Trichinaکہتے ہیں۔سٹاہل (Stahl) نے اس موضوع پر اپنی کتاب This Wormy World میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت دنیا میں قریبا تین کروڑ کی تعداد میں لوگ اس بیماری کے شکار ہیں۔ لاعلمی پر مبنی خیالات کے برخلاف اوپر بیان کردہ بیماری ٹرائی کینا دماغ میں صرف نقصان دہ گلٹی یا تھیلی ہی نہیں بناتی بلکہ چونکہ سور سے پھیلائی گئی یہ وبا خون میں رکاوٹ یا منجمد کرنے کا عمل بھی پیدا کرتی ہے، اس لیے اس سے ٹائیفائڈ جیسا موذی مرض بھی پیدا ہوتا ہے اور اس سے اچانک موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سور کا گوشت جسم کے پٹھوں میں مرکوز ہو کر پٹھوں کی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔
سور سے متعلق مخصوص چوڑے خنزیری کیڑے (Tape Worm)والی ایک اور بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے یورپی ممالک میں سور کے پھیپھڑوں کا کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ مگر سور کے عام گوشت کے ذریعہ بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ انسانی صحت کو سب سے زیادہ نقصان اس بیماری سے ہوتا ہے جس سے اس جانور کے گردوں کی سخت چربی کے ذریعے آنتوں میں خاص قسم کے طفیلی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام فہم بات ہے کہ جانوروں کے گوشت میں دو قسم کی چربی ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی تو وہ ہے جو صاف نظر آتی ہے اور گوشت کے اوپر لپٹی ہوتی ہے جبکہ دوسری قسم کی چربی وہ ہوتی ہے جو خود گوشت کے پٹھوں کے ریشوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ جہاں تک چربی کا گوشت میں مرکوز ہو جانے کا معاملہہے، دوسری قسم کی چربی سے بطور خاص ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں عام قسم کے گوشت کی چیزوں میں چربی کا مرکوز ہو جانا درج ذیل ہے۔
بچھڑے کا گوشت (۱۰ فیصد)
بھیڑ کاگوشت (۲۰ فیصد)
بھیڑکے بچے کا گوشت (۲۳ فیصد)
سؤر کا گوشت (۳۵ فیصد)
جانوروں سے حاصل کردہ چربی جو ہمارے جسم میں جاتی ہے، اس کے متعلق یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ انسانی خون میں یہ سب سے کم مقدار میں تحلیل ہوتی یا گلتی ہے۔ چنانچہ اس کے کھانے سے خون میں چربی (Lipid) اور کولیسٹرول (Cholesterol) کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اجزا خون کے بہاؤ میں زیادہ عرصہ تک موجود رہیں تو یہ چپکنے سے رکاوٹ بناتے ہیں اور خون کی شریانوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ آج کل تو پوری طرح سے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خوراک میں چربی کا زیادہ مقدار میں ہونا ہی دل کی شریانوں کی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ خون میں چربی کی مقدار کا ضرورت سے زیادہ ہونا وقت سے قبل بڑھاپے، ضعف، فالج اور دل کے دورے کی بلا شبہ ایک عام وجہ ہے۔
آج کل قصاب کی دوکان میں داخل ہونے والا ہر گاہک بغیر چربی کے گوشت کا طلب گار ہوتا ہے لیکن دراصل اس چربی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جو گوشت کے باہر ظاہری طور پر نظر آتی ہے بلکہ اس چربی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی مگر گوشت کے اندر پٹھوں کے ریشوں میں چھپی ہوتی ہے۔
سور کے گوشت میں بہت زیادہ چربی سے ایک اور نقصان یہ ہے کہ انسانی جسم میں وٹامن ای ضرورت سے کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا گوشت کھانے والوں میں وٹامن ای فورا تحلیل ہونے کے عمل سے اس وٹامن میں اندرونی مخفی کمی پید اہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ وٹامن ای بہت سے دل چسپ کام انجام دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کام وہ ہے جس کا جنسیاتی غدود (Sex Glands) پر اہم اثر ہے۔ موٹے لوگ، خاص طور پر سور کا گوشت کھانے والے لوگ وٹامن ای کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجتا جنسی طور پر سست او رنامرد ہو جاتے ہیں۔ وٹامن ای کی کمی رفتہ رفتہ مختلف قسم کی جلدی اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے۔
جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا کہ مستقل اور متواتر گندی اور غلیظ خوراک اور فضلہ کھانے سے سور کے جسم کا لمفی نظام متواتر حرکت میں رہتا ہے اور ان حفاظت دینے والے اجزا سے بھرا رہتا ہے جن میں مخصوص سفید چربی البومن (Albumin) پائی جاتی ہے۔ یہ اجزا جو جسم کے محفوظ رکھنے والے نظام(Immune System) میں پیدا ہوتے ہیں اور جن پر متعدی امراض سے متعلق تحقیقات ہو رہی ہیں، دوسرے جسیموں یا مخلوق کے لیے انتہائی زہریلے اور مہلک اثرات رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک جسیمہ یا مخلوق اپنے جسم کے خلیوں کی حفاظت کے لیے جو مخصوص قسم کے پروٹین پیدا کرتا ہے، وہی پروٹین دوسرے جسیمے یا اس کے کھانے والے کے خلیوں کے لیے زہر کا اثر رکھتا ہے۔ اس حقیقت کی بنا پر سؤر کے گوشت کے مسلسل استعمال سے مختلف الرجی قسم کی بیماریاں اور پٹھوں کی سوجن کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکا لیکن یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہی اجزا ہماری نسوں اور رطوبت پیدا کرنے والے لمفی نظام کے عمل میں انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں۔
چونکہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو بہت سی بیماریوں کا شکار رہتا ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کے گوشت کو کھانے اور ہضم کے ذریعے نقصان دہ سفید چربی والی البومنز، جنہیں اینٹی باڈی کہتے ہیں، انسانی جسم کے اندر داخل نہ ہو جائے۔
الغرض سور کا گوشت ایک ایسی خوراک ہے جسے نشوونما کے لیے نہیں بلکہ خود کو زہریلا مواد کھلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس سلسلے میں تمام قسم کے حقائق سامنے آ چکے ہیں اور وہ لوگ جو اس کو محض شوق اور دکھاوے کے لیے کھاتے ہیں، ان کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ خراب ہے۔
قرآن حکیم کی اس آیت کے ذریعے ایک اور اہم سبق جو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ سور کے گوشت کو خون اور مردار کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی مثال اس طرح ہے کہ نقصان دہ جراثیم اور جانوروں سے پیدا ہونے والے زہر (ٹاکسن) ا س نکمے گوشت یعنی جگر یا دل کے گوشت میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اسی قدر نقصان دہ اجزا سور کا گوشت مہیا کرتا ہے۔ ہماری توجہ بطور خاص خون میں پائی جانے والی رطوبت کے البومنز کا سور کے لمفی نظام سے پیدا ہونے والی البومنز کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں سور کے گوشت کو مردار کے گوشت سے اس لیے ملا دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں جراثیم سے آلودہ گندگی پائی جاتی ہے اور خون سے اس لیے ملایا گیا ہے کہ دونوں کے البومنز میں نقصان دہ رطوبت پائی جاتی ہے۔
ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم اس فرمان کے ذریعے سے ایک بلا وجہ قسم کی نکتہ چینی نہیں کر رہا بلکہ انسانی صحت وتندرستی کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ پیش کر رہا ہے۔
حیران کن بات یہ ہے کہ سور کے گوشت کے ان نقصانات کا وسیع طو رپر علم ہو جانے کے بعد بھی اس کو متواتر کھایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں معاشی عوامل کا خاصا دخل ہے۔ مگر بہت جلد یہ چیز صحت کے لیے ایک خطرناک مسئلہ بن جائے گی۔ آج کل تو یہ بالکل عیاں بات ہے کہ دل اور خون کی شریانوں کی بیماریاں ان معاشروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جہاں سور کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ پھر بھی تاحال سور کے گوشت میں ضرورت سے زیادہ چربی کا وجود عوام میں تشویش یا بحث مباحثے کا موضوع نہیں بنا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اب ایجنڈے پر آ چکا ہے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا مستقبل قریب میں قرآن حکیم کے حکم کے مطابق سؤر کے گوشت سے اجتناب کر لے گی۔
آخر میں ہم اس سائنسی نقطہ نظر کو پیش کریں گے جس میں سور کے گوشت سے متعلق ایک اور اہم بات کی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان دانش وروں نے دعوی کیا ہے کہ صرف سور ہی ایک ایسا جانور ہے جس میں اپنی مادہ کے سلسلے میں کسی قسم کے حسد یا غیرت کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ اور اس لیے وہ اس کے لیے لڑائی بھی نہیں کرتا۔ اسی نسبت سے سور کھانے والے لوگ اور قومیں بھی جنسی طور پر بے غیرت ہوتی ہیں۔
فہم قرآن کے ذرائع ووسائل
محمد عمار خان ناصر
قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے اس کے فہم کی اولین شرط عربی زبان کا مناسب علم ہے۔ لیکن محض عربی زبان کا علم فہم قرآن کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ قرآن کے نظم، اس کے زمانہ نزول کے حالات، کتب سابقہ اور حدیث وسنت کا علم بھی فہم قرآن کے لیے لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ذیل میں ہم فہم قرآن کے ان ذرائع کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔
قرآن کا نظم
کسی بھی کلام کے صحیح مفہوم کی تعیین میں اس کے نظم اور سیاق وسباق کی رعایت ایک بنیادی شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی متکلم جب کلام کرتا ہے تو وہ بات کے تمام اجزا کو الفاظ میں بیان نہیں کرتا بلکہ ایسی بیشتر باتوں کو حذف کر دیتا ہے جن کو اس کا مخاطب اپنے سابق علم، متکلم کے ساتھ اپنے تعلقات ، اس کے لہجے، کلام کی ترتیب اور اس ماحول کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے جس میں کلام کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام لواحق کلام کے صحیح فہم کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور کسی بھی کلام کو اگر اس کے ان لواحق سے ہٹا کر پیش کیا جائے تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ نہ صرف متکلم کی منشا کا درست ابلاغ نہ ہو پائے گا بلکہ بعض صورتوں میں کلام کا مفہوم متکلم کی مراد کے بالکل الٹ لے لیا جائے گا۔
اس عام عقلی اصول کا اطلاق کتاب اللہ پر بھی ہوتا ہے۔چنانچہ دیکھئے:
صحیح مفہوم کی تعیین
قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اگر سیاق وسباق کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو آیات کا انفرادی مفہوم خبط ہو کر رہ جاتا ہے۔ گمراہ فرقوں نے بیشتر اسی طریقے سے اپنی گمراہیوں کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔
مثلا سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے :
ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصاری والصابئین من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلھم اجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہود ونصاری اور صابئین، ان میں جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو ان کے رب کے ہاں اپنا اجر ملے گا اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (۱)
ملحدین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ نجات کے لیے رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ اس کا مدار ایمان باللہ ، ایمان بالآخرۃ اور اعمال صالحہ پر ہے ۔ لیکن اگر اس آیت کے سیاق کو دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ یہ ان عقائد کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نہیں آئی جو نجات کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہود کے اس عقیدہ کی تردید کے لیے آئی ہے کہ وہ نسلی اعتبار سے خدا کی منتخب قوم ہیں اور محض اس بنا پر آخرت میں خدا کی نعمتوں اور رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی خاص گروہ یا قوم سے متعلق ہونا نجات کے لیے معتبر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے۔ چونکہ یہ بات ایک عام قاعدہ کی حیثیت سے بیان کی گئی ہے اور اس کا اطلاق رسول اللہ ﷺ سے پہلے گزر جانے والے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا ذکر ناموزوں تھا۔ چنانچہ صرف وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جو آیت میں مذکور تمام گروہوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی تھیں۔
اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے :
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔(۲)
منکرین ختم نبوت نے اس آیت میں خاتم النبیین کے لفظ کے قطعی مفہوم میں تحریف کرتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے :’’نبیوں پر مہر لگانے والا یعنی ان کی تصدیق کرنے والا‘‘ اور اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگرچہ حسی لحاظ سے آپ کی کو ئی نرینہ اولاد نہیں ہے لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی تصدیق سے آپ کی امت میں اور بھی نبی ہوں گے جو آپ کی روحانی اولاد ہوں گے۔
آیت کے مفہوم میں یہ تحریف اس کے سیاق کو نظر انداز کیے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے متبنی حضرت زید بن حارثہؓ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؓ کے نکاح اور پھر جدائی کے واقعہ کے ضمن میں آئی ہے۔ عرب کے معاشرے میں متبنی کو حقیقی بیٹے ہی کا مقام دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تعالی کے حکم سے حضرت زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد رسو ل اللہ ﷺ نے حضرت زینبؓ سے خود نکاح کر لیا تو منافقین نے اس کو غوغا آرائی اور فتنہ انگیزی کا سامان بنا لیا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ عرب معاشرہ کی اس غلط رسم کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد مذکورہ آیت ہے جس کا مقصد، ا س تناظر میں، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتاکہ چونکہ محمد ﷺ اللہ کے آخری نبی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام بد رسوم کا خاتمہ اپنی زندگی ہی میں کر جائیں۔
اس کی ایک اور مثال سورۃ الجن میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے :
عالم الغیب فلا یظھر علی غیبہ احدا ۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔
اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب فرماتا ہے تو وہ ان کے آگے اور پیچھے پہرہ رکھتا ہے۔(۳)
اس آیت میں مفسرین نے بالعموم الا کو استثنا کے مفہوم میں لیا ہے جس سے بعض گمراہ فرقوں کو یہ استدلال کرنے کا موقع مل گیا کہ اللہ تعالی انبیاء کو بھی علم غیب عطا کرتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ علم الغیب اور اطلاع علی الغیب میں کیا فرق ہے، اگر ان آیات کے سیاق کو ملحوظ رکھا جائے تو اس استدلال کی بالکل نفی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس آیت سے متصل پچھلی آیت یہ ہے :
قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا۔ عالم الغیب فلا یظھر علی غیبہ احدا۔
اعلان کر دیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہی ہے یا ابھی اللہ اس کو کچھ دیر اور ٹالے گا۔
یہ آیات دراصل مشرکین کے مطالبہ عذاب کے جواب میں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ عذاب کے وقت کا مجھے کوئی علم نہیں کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور وہ اپنے غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا۔ اب اگر اگلی آیت میں الا کو استثنا کے معنی میں لے کر انبیاء کے لیے علم غیب کا اثبات کیا جائے تو پچھلے استدلال کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا بنیادی نکتہ ہی یہ ہے کہ پیغمبر کو عذاب کے وقت کا علم نہیں اس لیے کہ اس کا تعلق غیب کے ان معاملات سے ہے جن کی اطلاع اللہ تعالی کسی کو نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ محقق مفسرین نے یہاں الا کو استثنا کے بجائے لکن کے معنی میں لیاہے۔ (۴)
حکمت قرآن
معرفت نظم کی دوسری اہمیت حکمت قرآن کے استنباط کے حوالے سے ہے۔ قرآن کی حکمت ، فی الواقع، اس کے نظم میں پوشیدہ ہے اور نظم کی معرفت ہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے سے اس لازوال خزانے تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ لکھتے ہیں :
’’نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر وقیمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی اصل قدر وقیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اس کی حکمت تک رسائی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن کو پڑھے گا، وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ منفرد احکام اور مفرد قسم کی ہدایات ہیں۔
اگرچہ ایک اعلی کتاب کے منفرد احکام اور اس کی مفرد ہدایات کی بھی بڑی قدر وقیمت ہے لیکن آسمان وزمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات وخواص معلوم کر لیں اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزا سے کوئی کیمیا اثر نسخہ ترتیب دے دے۔ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالا استعمال ہوا ہے، وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی ہے۔ میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فقروں سے ترکیب پایا ہے، وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبان ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے ان کو وہ جمال وکمال بخش دیا ہے کہ اس زمین کی کوئی چیز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام بڑی نیکیوں کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں لیکن وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے۔ جو شخص دین کی حکمت سمجھنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر وشر کے ان تمام مراحل ومراتب سے اچھی طرح واقف ہو۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ دق کا پتہ دینے والی بیماری کو نزلے کا پیش خیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد آمد کو دق کا مقدمۃ الجیش قرار دے دے۔ قرآن کی یہ حکمت اجزائے کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو لیکن سورہ کے اندر ان آیتوں کے باہمی حکیمانہ نظم سے واقف نہ ہو تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف اصولی باتوں پر آفاقی وانفسی یا تاریخی دلائل بیان کیے ہیں۔ یہ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو، وہ جب اس سورہ کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اس نے ایک نہایت جامع، مدلل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑھا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اس ترتیب سے بے خبر ہو، وہ اجزا سے اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس حکمت سے وہ بالکل ہی محروم رہتا ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہوتی ہے۔‘‘ (۵)
اس کی ایک مثال سورہ بقرہ کے اس حصے میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں شریعت کے احکام وقوانین بیان ہوئے ہیں۔ اس باب کے مضامین کی ترتیب یہ ہے :
توحید اور اس کے متعلقات (آیات ۱۶۳ تا ۱۷۶)
توحید کے ثمرات مثلا ایمان، انفاق، اقامت صلوۃ، ادائے زکوۃ، ایفائے عہد اور حق پر استقامت (۱۷۷)
قصاص کے احکام (۱۷۸، ۱۷۹)
وصیت اور اس میں تبدیلی کے احکام (۱۸۰، ۱۸۲)
روزے کے احکام (۱۸۳ تا ۱۸۷)
رشوت خوری کی ممانعت (۱۸۸)
جہا،د حج اور انفاق کے متعلق ہدایات (۱۸۹ تا ۲۲۱)
حیض، طلاق اور رضاعت کے مسائل (۲۲۲ تا ۲۳۷)
نماز پر محافظت کی تاکید (۲۳۸)
اس حصے کا آغاز توحید کے بیان سے ہوا ہے کیونکہ تمام دین کی بنیاد اسی پر ہے۔ اس کے بعد توحید کے ثمرات بیان ہوئے ہیں اور مختلف معاملات میں شریعت کے احکام بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دین محض چند رسوم وظواہر کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی سے نہایت گہرا تعلق رکھنے والے اعمال واخلاق کا مجموعہ ہے، لہذا وہ اگلی امتوں کی طرح صرف رسوم کے بندے بن کر نہ رہ جائیں بلکہ دین کی اصلی حقیقتوں کو اپنائیں۔ نیکی اور تقوی کی اصل حقیقت واضح کرنے کے بعد ان معاملات کی طرف توجہ فرمائی جو تقوی پر مبنی ہیں اور جن پر معاشرہ کے امن اور بقا کا مدار ہے۔ اس ضمن میں حرمت جان کے حوالے سے قصاص اور حرمت مال کے حوالے سے وصیت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد روزے کے احکام کا ذکر ہے جن کے متصل بعد رشوت اور حرام خوری کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ جان ومال کے احترام اور حرمت رشوت کے احکام کے درمیان میں روزے کے احکام کے ذکر سے مقصد روزے کے اغراض ومقاصد اور اس کے فوائد کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ گویا روزہ جس طرح دوسروں کی جان ومال کے احترام کے حوالے سے نفس کی تربیت کرتا ہے، اسی طرح رشوت اور حرام خوری سے بچنے کے لیے بھی صبر کی اساس فراہم کرتا ہے۔ اسی صبر واستقامت کی اساس پر دین کی دو بڑی عبادتیں حج اور جہاد قائم ہیں، چنانچہ اس کے بعد ان کا ذکر کیا گیا ہے ۔ جہاد کے ساتھ انفاق کی خاص مناسبت ہے، اس لیے اس کے متعلق بھی بعض ہدایات ذکر کی گئی ہیں۔ اسی انفاق کے ضمن میں یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ بیان ہوا جس سے نکاح وطلاق اور رضاعت کے متعلق شریعت کی عمومی ہدایات بیان کرنے کے لیے بھی ایک مناسب موقع پیدا ہو گیا۔ اس باب کا اختتام نماز پر محافظت کی تاکید سے ہوا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’اس باب کے آغاز پرنظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس کے آغاز میں توحید کے ذکر کے بعد احکام شریعت کے سلسلہ میں سب سے پہلے آیت ۱۷۷ میں نماز اور ساتھ ہی زکوۃ کا ذکر آتا ہے۔ یہاں دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس باب کا خاتمہ بھی نماز ہی کے ذکر پر ہوا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دین میں جو اہمیت نماز کی ہے وہ دوسری کسی چیز کی بھی نہیں ہے۔ ساری شریعت کا قیام وبقا اسی کے قیام وبقا پر منحصر ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو شریعت کی اقامت اور اس کی محافظت کے لیے ایک حصار اور ایک باڑھ کی حیثیت دی ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت کرتا ہے وہ گویا پوری شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور جو شخص اس میں رخنے پیدا کرتا ہے وہ ، جیسا کہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے، باقی دین کو بدرجہ اولی ضائع کر دیتا ہے۔‘‘ (۶)
مولانا ؒ نے ربط کلام کی اس وجہ کی تائید میں سورۂ مومنون اور سورۂ معارج کی آیات بطور نظیر نقل کی ہیں جن میں اسی اسلوب پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز دین کے لیے بمنزلہ حصار کے ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :
قد افلح المومنون ۔ الذین ھم فی صلاتھم خاشعون۔
ایمان لانے والے یقیناًکامیاب ہیں، وہ جو اپنی نمازیں عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔
اس کے بعد دین واخلاق کی چند بنیادی باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں پھر فرمایا ہے :
والذین ھم علی صلواتھم یحافظون۔
اور وہ جو اپنی نمازوں کی مکمل پابندی کرتے ہیں۔ (۷)
بعینہ یہی اسلوب سورۂ معارج کی آیات ۱۹۔۳۴ میں پایا جاتا ہے۔
زمانہ نزول کے حالات
قرآن مجید اپنے پیغام اور تعلیمات کے لحاظ سے اگرچہ ایک آفاقی کلام ہے لیکن اپنے نزول کے لحاظ سے ایک خاص پس منظر رکھتا ہے۔ اس کے مخاطب ایک خاص سرزمین اور خاص زمانہ میں رہنے والے لوگ تھے جن کے عقائد واعمال اور معاشرت کی اصلاح کو اس نے اپنا موضوع بنایا۔ اس کا نزول رسول اللہ ﷺ کی تیئیس سالہ مدت دعوت میں مکمل ہوا اور اس کی ہدایات کا اس عرصہ میں پیش آنے والے مختلف حالات اور مراحل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید، اصلا، رسول اللہ ﷺ کی اس دعوت کی تاریخ ہے ۔ اس لحاظ سے اس کے مندرجات کو سمجھنے کے لیے ان خاص حالات سے عمومی طور پر واقفیت ضروری ہے جو اس کے تدریجی نزول کے پس منظر میں موجود تھے، اس لیے کہ قرآن اس خاص زمانہ کے مختلف گروہوں اور ان کے حالات کے متعلق جو اشارات کرتا ہے، اس کے مخاطبین کے لیے تو ان کو سمجھنا آسان تھا لیکن ہمارے لیے یہ اشارات بالعموم اس قدر مجمل اور مبہم ہیں کہ ان کا صحیح تصور ذہن میں قائم ہونا اس وقت تک مشکل ہے جب تک اس زمانے کی تاریخ سے واقفیت نہ ہو۔
اس واقفیت کے دو پہلو ہیں : ایک تو قرآن کے زمانہ نزول کے حالات اور اس کے مخاطب گروہوں کے معتقدات وخیالات اور ان کے معاشرتی حالات کا عمومی علم، اور دوسرا ان خاص جزوی واقعات سے آگاہی جو قرآن مجید کی بعض آیات کے نزول کا سبب بنیں۔
عمومی پس منظر
عمومی حالات سے آگاہی میں، مولانا حمید الدین فراہیؒ کے الفاظ میں، مندرجہ ذیل باتیں شامل ہیں:
(۱) ہم کو اس وقت کے یہود ونصاری ومشرکین وصابئین وغیرہ کے مذاہب ومعتقدات سے واقف ہونا چاہئے۔
(۲) ہم کو عرب کے عام توہمات کو دریافت کرنا چاہئے۔
(۳) ہم کو جاننا چاہئے کہ نزول قرآن کی مدت میں کیا کیا واقعات نئے پیدا ہوئے اور ان سے عرب کی مختلف جماعتوں میں کیا کیا مختلف باتیں زیر بحث آ گئیں، کیا کیا ملکی وتمدنی جھگڑے چھڑ گئے اور تمام عرب میں کیا شور ش پیدا ہو گئی؟
(۴) ہم کو یہ بھی جاننا چاہئے کہ عرب کس قدر وحشی اور تند مزاج تھے اور اس لیے کس قسم کے کلام سے متاثر ہو سکتے تھے۔
(۵) ہم کو یہ بھی جاننا چاہئے کہ عرب کا مذاق سخن کیا تھا، کس قسم کے کلام کے سننے اور بولنے کے وہ عادی تھے، رزم وبزم میں ان کا خطیب کس روش پر چلتا تھا، ایجاز واطناب، ترصیع وترکیب اور دیگر اسالیب خطابت وہ کیوں کر استعمال کرتے تھے۔
(۶) اور بالاخر ہم کو یہ بھی جاننا چاہئے کہ عرب کے ذہن میں اخلاق کے مدارج نیک وبد کیا تھے۔ (۸)
مشرکین عرب
۱۔ سورۃ البقرۃ میں جوئے اور شراب کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے : فیھما اثم کبیر ومنافع للناس۔ ’’ان میں گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں‘‘ ۔ (۹)
اس آیت کے متعلق بالعموم یہ سمجھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے جوئے او رشراب کی طبی اور ذاتی منفعت کا اعتراف کیا ہے جس کی بنیاد پر بعض ملحدین نے اس آیت سے شراب اور جوئے کا جواز کشید کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر عرب کے تمدنی حالات پر نظر ہو تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد ان کی تمدنی اور معاشرتی منفعت ہے۔ عرب کے فیاض او رسخی طبیعت کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قحط کے موسم میں اکٹھے ہو کر شراب نوشی کی مجلسیں بپا کرتے تھے اور نشے میں مست ہو کر اپنے اونٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے ۔ پھر ان کے گوشت کی ڈھیریاں لگا کر ان پر جوا کھیلتے اور جو گوشت جیتتے، اس کو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتے تھے۔ جوئے اور شراب سے حاصل ہونے والی یہی وہ معاشرتی منفعت تھی جس کی بنا پر جب قرآن مجید نے ان کی حرمت کا اعلان کیا تو بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ یہ مفید چیزیں کیوں حرام کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالی نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض تمدنی فوائد ضرور ہیں لیکن ان کے نقصانات کا پہلو ان فوائد کے مقابلے میں غالب ہے، اس لیے ان کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ (۱۰)
۲۔ سورۃ النساء میں محرمات کے بیان میں ارشاد ہے : وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم ’’تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں‘‘ (۱۱)
صلبی کی قید سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رضاعی بیٹوں کی بیویاں حرام نہیں ہیں لیکن اگر اس کے پس منظر میں موجود حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس قید سے مقصود، درحقیقت، لے پالک بیٹوں کو خارج کرنا ہے کیونکہ اہل عرب کے ہاں ان کو حقیقی بیٹوں کا مقام حاصل تھا جس کی اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب میں مفصل تردید کی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مفہوم مراد لیا ہے۔
۳۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیات ۱۳۶ تا ۱۴۰ میں چوپایوں کی حلت وحرمت کے متعلق عرب کے بہت سے توہمات کا ذکر ہوا اور انداز بیان اجمالی اشارات کا ہے۔ مخاطبین چونکہ ان رسوم سے پوری طرح باخبر تھے ، اس لیے ان کے لیے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب آج ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ان رسوم کے متعلق بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں جن کا جواب ظاہر ہے کہ اس دور کی عرب معاشرت کے مطالعہ ہی سے مل سکتا ہے۔
اہل کتاب
قرآن کے مخاطب گروہوں میں مشرکین مکہ کے بعد دوسرا بڑا گروہ یہود کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے انکار اور مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے انہوں نے جو جو جتن کیے اور کتمان حق کے لیے جو جو حیلے اختیار کیے، قرآن اسی اجمالی انداز میں ان کا ذکر کرتا اور ان کی چالاکیوں کا پردہ چاک کرتا ہے۔ ان اشارات کی تفصیل اور یہودیوں کی خباثتوں سے پوری طرح آگاہی حاصل کرنے کے لیے بھی دور نبوت کے حالات کا مطالعہ ضروری ہے۔
حکمت قرآن
آیات کے نفس مفہوم کی تعیین کے علاوہ ، زمانہ نزول کے حالات سے واقفیت کا نہایت گہرا تعلق قرآن مجید کی بعض ہدایات واحکامات کی حکمت سمجھنے سے بھی ہے۔مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو بیت الحرام کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، رسول اللہ ﷺ کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی، حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کے نکاح اور پھر ان سے جدائی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان سے کیوں نکاح کیا، قرآن مجید نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں قرار دیا، یہ اور اس طرح کے دوسرے سوالوں کا جواب پانے اور اس باب میں قرآن کی ہدایات کی معنویت اور مناسبت سمجھنے کے لیے دور نبوت کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ ازبس ضروری ہے۔
خاص آیات کا شان نزول
قرآن مجید میںآیات کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے نزول کا سبب کوئی خاص واقعہ یا حالت تھی جو اگر پیش نظر نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ متعلقہ آیتوں کے اشارات صحیح طور پر سمجھے نہیں جا سکتے بلکہ بعض صورتوں میں نفس مفہوم کے اخذ کرنے میں بھی غلطی کا امکان غالب ہے۔ ایسے مواقع پر شان نزول سے واقفیت اس قدر اہم ہے کہ بعض صحابہ بھی عربی زبان سے براہ راست واقفیت اور زمانہ نزول کے عمومی حالات سے باخبر ہونے کے باوجود بعض آیات کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔
۱۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عروہ بن زبیرؓ نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے صفا ومروہ کی سعی کے بارے میں فرمایا ہے:
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بھما۔
جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس پر کوئی گناہ کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی سعی نہ بھی کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا : بھتیجے، تم غلط کہتے ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالی یوں فرماتے : لا جناح علیہ ان لا یطوف بھما۔ (اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان کے درمیان سعی نہ کرے) یہ آیت درحقیقت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مشلل کے مقام پر منات کا طواف کیا کرتے تھے اور صفا ومروہ کے مابین سعی کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (۱۲)
۲۔ سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہے :
نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم۔
تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو۔ (۱۳)
اس آیت کی بنیاد پر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فتوی دے دیا کہ آدمی اپنی بیوی سے اس کی دبر میں بھی مجامعت کر سکتا ہے۔ (۱۴) سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کو علم ہوا تو انہوں نے فرمایا: اللہ ابن عمر کو معاف کرے، بخدا ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مدینہ میں انصار کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے اور انصار ان کو علمی لحاظ سے برتر سمجھتے اور بہت سی باتوں میں ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ یہود کے ہاں عورتوں سے صرف ایک ہی طریقے پر (یعنی سیدھا لٹا کر) مجامعت کرنا جائز تھا اور انصار نے بھی ان کی پیروی میں یہی طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کے برخلاف قریش کے لوگوں میں عورتوں سے مختلف طریقوں سے (مثلا لٹا کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے ) جماع کرنے کا طریقہ رائج تھا۔ جب مہاجرین مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انصار میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے ساتھ قریش کے طریقے پر جماع کرنا چاہا لیکن اس عورت نے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان بات بڑھ گئی اور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گئی۔ اس پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی جس کا مطلب یہ ہے کہ جماع کا محل تو ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے تم طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہو۔ (۱۵)
اس باب میں یہ بات، البتہ، ملحوظ رہنی چاہئے کہ اگرچہ کسی واقعہ کی بنیادی تصویر معلوم کرنے کے لیے شان نزول کی روایات کی طرف رجوع کرنا ناگزیر ہے لیکن اس کی تفصیلات بہرحال قرآن کی داخلی شہادت کی کسوٹی پر پرکھ کر ہی قبول کی جائیں گی۔ روایات کو کسی بھی صورت میں قرآن پر حکم نہیں بنایا جا سکتا۔ درج ذیل دو مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔
۱۔ غزوۂ بدر کی تفصیلات میں وارد روایات میں بالعموم یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے لشکر کو لے کر مدینے سے نکلے تو مسلمانوں کے سامنے اصل ہدف قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹنا تھا، مکے سے آنے والے لشکر کے ساتھ جنگ کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی ؒ نے ان روایات کو قرآن مجید کی حسب ذیل آیات کی روشنی میں رد کر دیا ہے :
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المومنین لکارھون۔
جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا حق کے ساتھ جبکہ مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا تھا۔ (۱۶)
شبلیؒ کہتے ہیں کہ وان میں واؤ حالیہ ہے جس کی رو سے مدینہ سے نکلنے اور ایک گروہ کے لڑائی سے جی چرانے کا زمانہ ایک ہونا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ موقع عین وہ موقع تھا جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے، نہ کہ مدینہ سے نکل کر جب آپ آگے بڑھے۔ (۱۷)
۲۔ غزوۂ بدر ہی کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی جو شان نزول کی روایات سے پیدا ہوتی ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں رسول اللہ ﷺاور مسلمانوں کو مشرکین کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے پر عتاب کیا گیا ہے :
ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرۃ واللہ عزیز حکیم ۔ لولا کتب من اللہ سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم۔
کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کو قید ی ہاتھ آئیں یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خونریزی برپا کر دے۔ یہ تم ہو جو دنیا کے سروسامان کے طالب ہو۔ اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو روش تم نے اختیار کی ہے‘ اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم آ پڑتا۔(۱۸)
مولانا امین احسن اصلا حیؒ اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فدیہ لے کر چھوڑنا سرے سے کوئی غلطی ہی نہ تھی کیونکہ اس کی اجازت اس سے پہلے سورہ محمد میں دی جا چکی تھی اوریہاں بھی اللہ تعالی نے اس کے معا بعد اس عمل کی تصدیق فرمائی ہے :
فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا۔
تو وہ حلال وطیب مال کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے (۱۹)
اور اگر بالفرض یہ غلطی بھی تھی تو اس کی نوعیت کسی سابق ممانعت کی خلاف ورزی کی نہیں تھی جس پر ایسی سخت وعید وارد ہو، کیونکہ اس قدر سخت الفاظ میں قرآن مجید نے کٹر کفار اور منافقین کے سوا اور کسی کو عتاب نہیں کیا۔ ان وجوہ کی بنا پر مولانا فرماتے ہیں کہ اس وعید کے مخاطب کفار ہیں جنہوں نے بدر میں شکست کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ نبی معاذ اللہ ہوس اقتدار میں مبتلا ہیں، انہوں نے اپنی ہی قوم میں خونریزی کرائی ، اپنے بھائیوں کو قید کیا ، ان کا مال لوٹااور ان سے فدیہ وصول کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی تنزیہ کی ہے اور کفار کو عتاب کیا ہے کہ یہ تو تمہیں صرف ایک چرکا لگا ہے جس پر تم اس قدر واویلا کر رہے ہو، اگر اللہ نے ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر نہ کر رکھا ہوتا تو تمہیں اسی موقع پرا یک عذاب عظیم آپکڑتا۔ (۲۰)
سابقہ آسمانی کتب
قرآن مجید کے مطالعہ میں کتب سابقہ کا علم مختلف پہلوؤں سے مددگارہے۔
اہل کتاب پر اتمام حجت
قرآن مجید نے سورہ بقرہ اور سورۃ المائدہ میں یہود کی سابقہ تاریخ کے حوالے سے ان کے مذہبی جرائم کا تذکرہ بالتفصیل کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہود نے کس کس طرح اللہ کے رسولوں کو ستایا اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں ہٹ دھرمی اور ضد کا رویہ اختیار کیا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے ان کے جرائم کی پاداش میں ان پر بحیثیت قوم جو ذلت مسلط کی، اس کا بھی جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ کتب سابقہ کے مطالعہ سے یہود کے اس رویے کی تائید وتفصیل بھی مہیا ہو سکتی ہے اور اہل کتاب پر خود انہی کی کتاب کی روشنی میں اتمام حجت بھی کی جا سکتی ہے۔
اہل کتاب کی تحریفات کی اصلاح
قرآن مجید نے سوۃ المائدہ میں خود کو سابقہ کتابوں کا مہیمن یعنی نگران قرار دیا ہے۔ اسی سورہ میں دوسری جگہ ارشاد ہے :
یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔
یہ رسول تمہارے سامنے تورات کی بہت سی وہ باتیں بیان کرتے ہیں جن کو تم چھپاتے رہے۔ (۲۱)
گویا قرآن کے نزول کا ایک بنیادی مقصد اہل کتاب کی تحریفات کی اصلاح ہے۔ انبیاء سابقین نے رسول اللہ ﷺ کے حق میں جو بشارتیں دی تھیں، یہود نے ان میں تحریف کر کے ان کو چھپانے کی کوشش کی ۔ خود انبیاء سابقین کے متعلق انہوں نے بے بنیاد قصے گھڑ کر ان کی شخصیات پر کیچڑ اچھالا۔ اسی طرح نصاری حضرت عیسی علیہ السلام کی ذات کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا تھے اور رسول اللہ ﷺ کے حق میں حضرت مسیح علیہ السلام کی واضح بشارت میں تحریف کر چکے تھے۔ قرآن مجید نے اس طرح کی تمام تحریفات کا پردہ چاک کیا اور تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا:
یجدونہ عندھم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔
یہ اس پیغمبر کو اپنے ہاں تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں (۲۲)
سورۃ البقرۃ میں فرمایا:
وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔
سلیمان نے بالکل کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ (۲۳)
سورۃ النساء میں فرمایا:
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لھم۔
وہ مسیح کو نہ قتل کر سکے اور نہ سولی دے سکے بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ (۲۴)
سورۃ الصف میں فرمایا:
ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔
(عیسی علیہ السلام نے کہا ) اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ (۲۵)
ہمارے اہل علم میں سے جن لوگوں نے کتب سابقہ اور ان سے متعلق لٹریچر کاگہرا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے ان امور کی تحقیق میں گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ برصغیر میں مولانا حمید الدین فراہیؒ کا رسالہ ’’ذبیح کون ہے؟‘‘ ، سورۃ الصف میں بشارت عیسی علیہ السلام کے تحت مولانا سید ابو الاعلی مودددیؒ کی اور ولکن شبہ لہم کی تفسیر میں مولانا عبد الماجد دریابادیؒ کی تحقیقات اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔
اسی طرح یہود کی تاریخ کے بہت سے واقعات کے بارے میں قرآن کا بیان بائبل کے بیان سے مختلف ہے۔ اس حوالے سے بھی قرآن کے بیانات کی معنویت اس کے بغیر واضح نہیں ہو سکتی کہ ان کا موازنہ کتب سابقہ کے بیانات سے کر کے دیکھا جائے۔
انبیاء کی تاریخ اور دین کی حکمت
قرآن مجید نے بعض مقامات پر کتب سابقہ کا ذکر اس انداز میں کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنے قارئین سے یہ چاہتا ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ سورۃ الاعلی کے آخر میں فرمایا:
ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ صحف ابراھیم وموسی۔
یہی تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی ہے، موسی اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ (۲۶)
واقعہ یہ ہے کہ بے شمار تحریفات کے باوجود آج بھی ان صحائف میں اصل آسمانی تعلیمات کے اجزاء موجود ہیں اور دین کی حکمت سمجھنے میں ان سے بیش بہا مدد مل سکتی ہے۔
سنت اور امت کا تواترعملی
سنت سے مراد دین کے وہ عملی احکام ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے اس امت میں جاری فرمایا اور جنہیں امت مسلمہ کی ہر نسل اپنے تواتر عملی کے ذریعے سے اگلی نسل تک منتقل کرتی چلی آ رہی ہے۔
قرآن کی بنیادی اصطلاحات
رسول اللہ ﷺ درحقیقت کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے تھے بلکہ آپ نے ملت ابراہیمی ہی کی ان تعلیمات وشعائر کا احیا کیا جو مرور زمانہ اور اہل عرب کی تحریفات کے نتیجے میں مسخ ہو چکی تھیں۔ اس دین میں صلوۃ، صوم، حج، نسک، نذراور اس طرح کے دوسرے احکام ایک معروف حقیقت کی حیثیت رکھتے تھے اور، تحریفات کے باوجود، ان کا بنیادی تصور بالکل مٹ نہیں گیا تھا۔ قرآن ان کا ذکر کسی نئے حکم کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر کرتا ہے جو اس کے مخاطبین کے نزدیک ثابت شدہ اور مانی ہوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ملت ابراہیمی کے انہی ثابت شدہ شعائر کو لے کر ان میں در آنے والی تحریفات کو دور کیا اور مناسب ترمیم واضافہ کے ساتھ انہیں امت مسلمہ میں ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دیا۔ یہ ملت ابراہیمی کی اصطلاحات ہیں جن کا مفہوم نسل در نسل تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے اور ان کے ثبوت یا ان کی بنیادی شکل وصورت کی تعیین میں ذرہ برابر بھی شبہے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی سنت اور امت مسلمہ کا تواتر عملی، قرآن کے ان بنیادی حقائق کی تفصیل کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
حدیث
حدیث رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات واقوال کا نام ہے جو آپ کے صحابہ نے انفرادی طور پر آپ سے سنے اور اسی طرح ان کو آگے نقل کر دیا۔ فہم قرآن میں حدیث کی اہمیت مختلف پہلوؤں سے ہے:
حکمت قرآن
رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر قرآن کا رمز شناس اور اس کے اسرا ر ومعانی سے آگاہ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کے بعض احکام کی ظاہری تشریح وتعبیر میں بھی بلا شبہ رسول اللہ ﷺ کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ کے خداداد علم وفہم اور پیغمبرانہ نکتہ شناسی کا اصل مظہر آپ کے ارشادات کا وہ حصہ ہے جس میں آپ نے قرآنی تعلیمات کے مغز کو پا کران کی توسیع بے شمار فروع کی طرف کی ہے اور اس طرح دین کو ایک مفصل ومرتب ضابطہ کی صورت میں مشکل کر دیا ہے ۔ آپ کے یہ ارشادات واقوال دین کے تمام شعبوں کو محیط ہیں اور حکمت دین کے سمجھنے میں جو رہنمائی ان سے ملتی ہے، اور کسی ذریعہ سے میسر نہیں ہو سکتی۔
قرآن کے مجمل کی تفصیل
قرآن مجید بالعموم کسی مسئلے کے بارے میں ایک حکم اصولی طور پر بیان فرما دیتا ہے لیکن اس سے متعلقہ جزوی امورکو مجمل چھوڑ دیتا ہے جن کی تفصیل رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں ملتی ہے۔ درج ذیل مثالیں ملاحظہ فرمائیے :
۱۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے محرمات کے ضمن میں ایسی عورت کو بھی شامل کیا ہے جس نے کسی بچے کو جنم تو نہیں دیا لیکن اس کو دودھ پلایا ہے۔ لیکن اس دودھ پلانے کی مقدار کیا ہو ؟ نیز کیا عمر کے کسی بھی حصے میں کسی عورت کا دودھ پینے سے وہ ماں بن جاتی ہے؟ اس معاملے میں قرآن خاموش ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:
لا تحرم المصۃ ولا المصتان۔
ایک یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی (۲۷)
انما الرضاعۃ من المجاعۃ۔
رضاعت کا اعتبار بچے کی دودھ پینے کی عمر میں ہے۔ (۲۸)
۲۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سفر کی حالت میں ہوں تو نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قصر نماز میں کتنی رکعتیں کم پڑھی جائیں، اس کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو واضح فرمایا ہے۔
۳۔ اسی کے متصل بعد اللہ تعالی نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر مسلمان حالت جنگ میں ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو ان کو اجازت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز کا کچھ حصہ پڑھ کر دشمن کے سامنے چلا جائے اور اس کی جگہ دوسرا گروہ آ جائے اور رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرے۔
یہ محض ایک اصولی حکم ہے جس کی عملی صورت قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ کی اس کی تفصیل فرمائی ہے اور آپ سے صلاۃ الخوف پڑھنے کے مختلف طریقے کتب احادیث میں نقل ہوئے ہیں ۔ (۲۹)
قرآن کے محتمل کی تعیین
قرآن مجید میں متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی مسئلے میں ایک حکم بیان فرمایا ہے جس کا اطلاق بعض صورتوں میں تو واضح ہے لیکن بعض صورتوں میں واضح نہیں بلکہ احتمال کے پہلو رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں حدیث دو یا زیادہ محتمل معنوں میں سے ایک کو متعین کر دیتی ہے۔ اس کی مثالیں حسب ذیل ہیں:
۱۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے مردار جانور کو حرام اور ذبح کیے ہوئے جانور کو حلال قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ذبح کیے ہوئے جانور کے پیٹ میں سے مردہ بچہ نکل آئے تو آیا وہ ایک مستقل وجود ہونے کے لحاظ سے مردار شمار ہوگا یا ماں کا جز ہونے کے اعتبار سے مذبوح؟ قرآن کی منشا اس معاملے میں غیر واضح ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
ذکاتہ ذکاۃ امہ۔
اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ (۳۰)
۲۔ سورہ مائدہ ہی میں اللہ تعالی نے سدھائے ہوئے شکاری کتوں کے شکار کے بارے میں فرمایا ہے : فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ ’’جس جانور کو وہ تمہارے لیے شکار کریں، اس کو تم کھا سکتے ہو اور ان کو (شکار پر چھوڑتے ہوئے) اللہ کا نام لیا کرو‘‘ اس حکم کا اطلاق بعض صورتوں میں غیر واضح ہے۔ مثلااگر سدھایا ہوا کتا جانور کو شکار کر کے اس کا کچھ گوشت خود بھی کھالے یا اس کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شکار کرنے میں شامل ہو گیا ہو تو کیا حکم ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:
اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم اللہ علیہ، فان امسک علیک فادرکتہ حیا فاذبحہ، وان ادرکتہ قد قتل ولم یاکل منہ فکلہ، وان وجدت مع کلبک کلبا غیرہ وقد قتل فلا تاکل فانک لا تدری ایھما قتلہ۔
اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ اگر وہ تمہارے لیے شکار کو پکڑے اور تم اس کو زندہ پا لو تو اس کو ذبح کر لو۔ اگر تمہارے پہنچنے سے قبل مر جائے اور تمہارے کتے نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شامل ہو گیا ہو اور شکار مر چکا ہو تو اسے مت کھاؤ، کیونکہ معلوم نہیں ان میں سے کس کتے نے اسے شکار کیا ہے۔ (۳۱)
۳۔ سورۃ البقرہ میں ایسی عورتوں کوجن کے خاوند فوت ہو گئے ہوں، چار ماہ دس دن تک عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ سورۃ الطلاق میں حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل بتائی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ کون سی عدت گزارے گی؟ اس میں عقلی لحاظ سے دونوں احتمال ہیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعیین کرتے ہوئے ایسی صورت میں وضع حمل کو عدت قرار دیا ہے۔ (۳۲)
بعض اشکالات کا حل
فہم قرآن سے متعلق بعض اشکالات کا حل بھی رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں ملتا ہے۔
۱۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی : الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانھم بظلم اولئک لھم الامن وھم مھتدون (جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے شائبے سے بھی پاک رکھا، انہی کو امن حاصل ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہیں) تو صحابہؓ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اشکال پیش کیا کہ ہم میں سے کون آدمی ہے جس نے کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک ہے: ان الشرک لظلم عظیم (۳۳)
۲۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ قرآن میں تو نماز قصر کر کے پڑھنے کی اجازت حالت خوف میں دی گئی ہے، جبکہ اب لوگ امن میں ہیں (پھر یہ رخصت کیوں ہے؟) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے رخصت ہے، سو اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرو۔ (۳۴) گویا آپ نے واضح فرمایا کہ قرآن میں حالت خوف کا ذکر بطور ایک لازمی شرط کے نہیں ہے۔
۳۔ جامع ترمذی میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری : من یعمل سوءًا یجز بہ (جو شخص جو بھی برائی کرے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا) توصحابہؓ نے اشکال پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم سب سے گناہ سرزد ہو تے ہیں تو کیا ہمیں ان سب کی سزا ملے گی؟ آپ نے فرمایا: مومن کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ (۳۵)
حوالہ جات
(۱) البقرہ، آیت ۶۲
(۲) الاحزاب، آیت ۴۰
(۳) الجن، آیت ۲۶، ۲۷
(۴) الآلوسی، سید محمود: روح المعانی،
(۵) اصلاحی، امین احسن: تدبر قرآن، دہلی: تاج کمپنی، ۱۹۹۹ء، جلد اول، ص ۲۰، ۲۱
(۶) المرجع السابق: ج ۱، ص ۵۴۹
(۷) المومنون، آیت ۱، ۲
(۸) فراہی، حمید الدین: ترتیب ونظام قرآن، مشمولہ قرآنی مقالات، لاہور: دار التذکیر، ۱۹۹۳ء، ص ۱۳
(۹) البقرہ، آیت ۲۱۹
(۱۰) تدبر قرآن، جلد اول، ص ۵۰۵
(۱۱) النساء، آیت ۲۳
(۱۲) البخاری، محمد بن اسماعیل: الجامع الصحیح، المملکۃ العربیۃ السعودیہ: دار السلام، ۲۰۰۰، کتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروۃ، حدیث نمبر ۱۶۴۳
(۱۳) البقرہ، آیت ۲۲۳
(۱۴) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورۃ البقرۃ ، حدیث نمبر ۴۵۲۷
(۱۵) ابو داؤد ، سلیمان بن اشعث السجستانی: سنن ابی داؤد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ: دار السلام، ۲۰۰۰، کتاب النکاح، باب فی جامع النکاح، حدیث نمبر ۲۱۶۴
(۱۶) الانفال، آیت ۵
(۱۷) شبلی نعمانی: سیرت النبی، لاہور : مکتبہ تعمیر انسانیت، ۱۹۷۵ء، ج ۱، ص ۳۲۵
(۱۸) الانفال، آیت ۶۷
(۱۹) الانفال، آیت ۶۹
(۲۰) تدبر قرآن، ج ۳، ص ۵۱۲، ۵۱۳
(۲۱) المائدہ، آیت ۱۵
(۲۲) الاعراف، آیت ۱۵۷
(۲۳) البقرہ، آیت ۱۰۲
(۲۴) النساء، آیت ۱۵۷
(۲۵) الصف، آیت ۶
(۲۶) الاعلی، آیت ۱۹، ۲۰
(۲۷) مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، المملکۃ العربیۃ السعودیہ: دار السلام، ۲۰۰۰، کتاب الرضاع، باب فی المصۃ والمصتان، حدیث ۳۵۹۰
(۲۸) صحیح البخاری : کتاب النکاح، باب من قال لا رضاع بعد الحولین، حدیث نمبر ۵۱۰۲
(۲۹) سنن ابی داؤد: دار السلام، ۲۰۰۰، کتاب الصلاۃ، باب صلوۃ الخوف، احادیث ۱۲۳۶ تا ۱۲۴۸
(۳۰) المرجع السابق، کتاب الضحایا، باب ما جاء فی ذکاۃ الجنین، حدیث نمبر ۲۸۲۷
(۳۱) صحیح مسلم، کتاب الصید والذبائح، باب الصید بالکلاب المعلمۃ والرمی، حدیث نمبر ۴۹۸۱
(۳۲) سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی عدۃ الحامل، حدیث نمبر ۲۳۰۶
(۳۳) صحیح البخاری : کتاب التفسیر، سورۃ الانعام، حدیث ۴۶۲۹
(۳۴) الترمذی، ابو عیسی محمد بن عیسی: جامع الترمذی، المملکۃ العربیۃ السعودیہ: دار السلام، ۲۰۰۰، کتاب التفسیر، سورۃ النساء، حدیث ۳۰۳۴
(۳۵) جامع الترمذی، کتاب التفسیر، سورۃ النساء، حدیث نمبر ۳۰۳۸
مغربی تہذیب کی یلغار
محمد شمیم اختر قاسمی
مسلمانوں کے ساتھ میڈیا کا معاندانہ رویہ
عصر حاضر میں ذرائع ابلاغ اور وسائل نے اتنی ترقی کی ہے کہ اور اس کا دائرۂ عمل اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ دنیا کا ہر گوشہ اس پر عیاں اور ہر جگہ اس کی پہنچ ہے۔ وہ جس واقعے کو جب اور جس وقت چاہے، اس کا واقعی یا خیالی پس منظر پیش کر سکتا ہے اور جس پر چاہے، پردہ ڈال سکتا ہے اگرچہ وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ بالخصوص امریکیوں کے پاس مسلمانوں کے خلاف میڈیا اور ذرائع ابلاغ کو چالاکی کے ساتھ پیش کرنے کے ایسے تمام نسخے موجود ہیں جس سے وہ مثلا اسامہ بن لادن کا سر کسی اور کے سر پر دکھا سکتے ہیں اور یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ اسامہ کسی عورت وغیرہ کو قتل کر رہا ہے۔ ان ذرائع کے اجارہ داروں کا یہ دعوی ہے کہ یہ سیکولرازم، آزادی رائے اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے علم بردار ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کا یہ دعوی واقعہ کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ان کے علمی اور تہذیبی کردار سے وہی قدیم صلیبی ذہنیت اور اسلام دشمنی اور مغربیت کی برتری کے تصور کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایسا ہی رویہ مسلمانوں کے ساتھ ملکی میڈیا کا بھی ہے اگرچہ اس کا تعلق صلیبی ذہنیت سے نہیں بلکہ سیاسی وسماجی اقدار سے ہے۔
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور ان کے مابین انتشار پیدا کرنے کی جتنی بھی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، وہ مغربی اور دیسی میڈیا استعمال کرتا ہے اور حقیقت واقعہ کو اس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے جس سے عوام بلکہ اسلامی ذہن رکھنے والے افراد بھی بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لیتے ہیں اور بلا اختیار سر ہلاتے ہوئے ان کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ ’’ایسا ہی ہوگا’’۔ ایسی صورت میں اسلام اور مسلمانوں سے بد ظن ہونے میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ درج ذیل واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میڈیا مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے:
’’نیو یارک ٹائمز‘‘ نے ایسے اڑتالیس مقامات کی نشان دہی کی جن میں ۱۹۹۳ء میں انسٹھ نسلی تصادم ہوئے اور یہ بتایا کہ ان میں سے آدھے تصادم وہ ہیں جو مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیے۔ (۱) یعنی مسلمانوں پر جو مظالم ہوئے، وہ بھی مسلمانوں ہی کے نامہ اعمال میں شمار کیے گئے۔ اسی طرح کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ ایک رات ٹیلی وژن پر اسلامی حکومت یمن کے حالات، وہاں کی مساجد، طرز تعلیم، نماز ودیگر عبادات اسلامی کے طریقے دکھا ئے جا رہے تھے۔ ٹیلی وژن سرزمین یمن کے باشندوں کی محرومیت کا تفصیل سے ذکر کرتے کرتے اسلام کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی چالاکی سے اسلام پر رقیق حملے شروع کر دیے کہ اس ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑا روڑا اسلام ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے قافلہ تمدن کو دو سو سال پیچھے کر دیا۔ ابتدائی مراحل میں توقف ، عقب نشینی یہ اسلام کا پروگرام ہے۔ آج کی دنیا میں پیدا ہونے والے مختلف انقلابات سے محرومی اسلام کی پیروی اور اس کے دستور کی پابندی کی وجہ سے ہے۔ (۲) ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو پولیس نے راستے میں اٹھا لیا اور اس پر وہ تمام الزامات لگائے جو حال میں قرب وجوار میں بم بلاسٹ ہوئے جس کو ملکی میڈیا نے خوب اچھالا اور بڑھا چڑھا کر بیان کیا یہاں تک کہ یونیورسٹی کو دہشت گردی کا سب سے بڑا اڈہ قرار دیا۔ ایک سرکاری افسر نے اپنے تحریری بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مبین نامی طالب علم بے گناہ ہے، ایک سوچھی سمجھی پالیسی کے تحت طالب علم کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس طرح یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری افسر نے ان تمام ارکان کے اوپر سے نیچے تک نام گنوائے ہیں جو یہ سازش کر رہے ہیں۔ مگر میڈیا اس تمام تحریری بیان کو ہضم کر گیا۔
بی بی سی ورلڈ سروس واحد نشریاتی ادارہ ہے جو ۲۴ گھنٹے مختلف زبانوں اور موضوعات پر خبریں اور معلوماتی پروگرام نشر کرتا رہتا ہے۔ شائقین قبل از وقت ہاتھ میں ریڈیو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ا س کی گوشمالی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اس کی کان لال نہ ہو جائے کیونکہ وہاں سے نشر ہونے والی زیادہ تر چیزیں مبنی بر حقائق ہوتی ہیں۔ مگر وہ بھی جب اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو غیر منصفانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی واقعی یا محض خیالی کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے، وہاں ان کے دل میں بد نیتی کی پر مسرت گدگدی ہونے لگتی ہے۔
قرآن وسنت، تاریخ اسلامی اور مسلمانوں کو ہدف بنا کر بے سروپا الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ اسی دوران دوسرے سماج میں عورتوں اور نچلے طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد پر کتنا ہی ظلم ہو، وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں کھلے عام عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے اور ہزاروں ناقابل رحم واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ بھارت میں ہر روز تین دلت عورتوں کی روزانہ عصمت دری کی جا تی ہے۔ اس پر کسی میڈیا کی انگلی نہیں اٹھتی۔ مگر جہاں کہیں مسلمان زوجین اور مسلم معاشرہ میں کوئی ناخوشگواری کی باتیں پیش آجاتی ہیں تو میڈیا لے اڑتا ہے اور غیر اسلامی افکار کے حامل اہل قلم حضرات اس پر اپنی قلمی توانائیاں صرف کرنے لگتے ہیں اور بغیر کسی رعایت اور پاسداری کے مسلمانوں کے مقدسات پر ان کے قلموں کی نوک کھل جاتی ہے۔ مشرق ومغرب کی ساری زیادتیاں خوبیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، عورتوں کے استحصال کے واقعات اور زوجین کی کش مکش کی داستانیں خیالی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح کے جارحانہ ویک طرفہ معاندانہ اقدامات سے مسلمانوں کے جذبات کو کچلا جاتا ہے۔ اگر مسلمان ان کے خلا ف آواز بلند اور جہدوجہد کرتے ہیں تو ان پر سختی کی جاتی ہے اور انہیں دہشت گرد کے القاب سے نوازا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے اور طرح طرح کی دردناک سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ ان کی آزائ رائے پر قدغن لگایا جاتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ مغربی میڈیا اور مغربی حکومتیں اپنی تابع دار حکومتوں کو مشورہ دیتی ہیں کہ مسلم عوام کو سختی سے کچل دیا جائے۔
جب کوئی بے ضمیر شخص اپنی شہرت یا مادی مفاد کی بنا پر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو دشمنان اسلام کے فکر وخیال سے ہم آہنگ ہوتی ہے تو اسے غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ (اس کی بہترین مثال سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات ہے) اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو خاموش رہنے بلکہ اس کے پراگندہ خیالات کو قبول کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے خیالات کو اکتشافات کا درجہ دے کر ان کی عالمگیر تشہیر کی جاتی ہے اور اس کو دنیا کا اتنا بڑا ہیرو قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے آگے عالمی فٹ بال اور کرکٹ کپ کا ہیرو بے وزن معلوم ہونے لگتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے دروازے ان کی حفاظت اور دفاع کے لیے کھل جاتے ہیں۔ (۳)
مشہور امریکی نقاد ایڈورڈ ڈبلو ساد اپنی کتاب ’’ذرائع ابلاغ اور اسلام‘‘ میں مغربی میڈیا کے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ معاندانہ رویہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے:
’’آج کل امریکہ اور یورپ میں عام لوگوں کے لیے اسلام کا مطلب ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر ناگوار خاطر ہیں۔ ذرائع ابلاغ، کومتیں اور دانش ور سب اس پر متفق ہیں کہ اسلام مغربی تمدن کے لیے خطرہ ہے۔ اسلام کی منفی باتیں دوسری باتوں کے مقابلے میں زیادہ رائج ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہے بلکہ اس لیے کہ سوسائٹی کا ایک مقتدر طبقہ ان کو ایسا ہی گردانتا ہے۔ یہ طبقہ بڑا بااثر ہے اور اس نے اسلام کے اس منفی تصور کو پھیلانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔‘‘ (۴)
’’میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ امریکہ میں ٹیلی وژن پر مقبول ترین اوقات میں شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں نسلی عداوت شامل نہ ہو اور جہاں مسلمانوں کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو اور جہاں مسلمانوں کو ’’جزک‘‘ کا نام دے کر برا بھلا نہ کہا گیا ہو۔ اسلام کے مقابلے میں امریکہ کی رائے عام یہ ہے کہ جو چیزیں انہیں ناپسند ہیں، وہ اسلامی ہیں۔‘‘ (۵)
ذرائع ابلاغ کی تباہ کاریاں
مغربی ذرائع ابلاغ نے انسانی دنیا کو کیا دیا، کیا سکھایا اور کن امور کے بجا لانے پر زور دیا؟ اس کی گہرائی میں ہم پہنچتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے دنیا کو جو کچھ ملا، ان میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بے حیائی، عریانیت اور فحاشی ہے جس کے تباہ کن اثرات سے پوری دنیا دوچار ہے، یہاں تک کہ مغرب کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔
اسٹار، زی، سونی اور دیگر ٹی وی چینل ۲۴ گھنٹے دلربا منظر پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایجاد نے ہر گھر کو وہ سینما ہال بنا دیا ہے جہاں زیادہ تر گندی اور عریاں فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے دیکھنے میں بڑے اور بچے ، مرد اورعورتیں ، یہاں تک کہ باپ بیٹی، بھائی بہن سب برابر کے شریک اور ایک ساتھ بیٹھ کر مزے لے لے کر دیکھتے ہیں جس کے گندے مناظر سے روح کانپ جاتی ہے۔خوبصورت عورت کو منظر عام پر لاکر دعوت نظارہ دی جاتی ہے۔ اشتہار کے نام پر بڑی بے ہودگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ سیریل ایسے کہ عشق کی داستان اور تشدد کے واقعات سے اخلاقی حس مردہ ہو جائے۔ غرض کہ اخلاق سوز اور مجرمانہ ذہنیت پیدا کرنے والی چیزیں پیش کر کے بڑے پیمانے پر بگاڑ کا سامان کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ٹی وی، ریڈیو کانوں اور آنکھوں دونوں کے لیے لذت کا سامان بن گیا ہے۔ شوق کا یہ عالم کہ گھر میں بیوی سے پہلے ٹی وی آ جاتا ہے۔ مغرب کی بات تو چھوڑ دیجیے کیونکہ وہ اخلاقی جذام میں مبتلا ہے۔ اس وقت مسلم معاشرہ اور اسلامی مملکتیں بھی اس بیماری کا پوری طرح شکار ہو گئی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں یہ وبا پھیل رہی ہے جس کی بنا پر نوجوانوں پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو محتاج بیان نہیں۔ کیا اس برائی کے ذمہ دار ہم خود نہیں ہیں؟ کم از کم مسلمانوں کو اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ وہ ایسے گندے وسائل کو اپنے گھروں اور معاشرے میں داخل نہ ہونے دیں۔ اگر مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے تو چاہئے کہ وہ مغرب کی تقلید کرنا ترک کر دیں۔
تفریح کے لیے ہم سرحد پار کی اخلاق دشمن فلموں، گانوں اور عریاں ویڈیو پروگراموں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور خود ہمارا ٹی وی احساس کمتری کا شکار ہونے کے سبب سرحد پار کے پروگراموں کی نقل کو اپنی فن کاری سمجھتا ہے۔ اس صورت حال میں ایک حل تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ٹی وی یا ویڈیو ہے تو آپ دونوں کو زمین میں دفن کر دیں اور خود کو یہ سمجھا لیں کہ آپ نے میڈیا کے شیطان کے خلاف جہاد کا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے کے باوجود آپ کے پڑوس میں ڈش پروہ سب کچھ آتا رہے گا جس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا ٹی وی اور ریڈیو زمین میں دفن کیا ہے اور خود آپ کے اپنے بچے اور پڑوس کے بچے شیطانی میڈیا سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ فنی کمال کے ساتھ متبادل پروگرام بنائیں جس میں ڈرامے بھی ہوں ،نغمے بھی ہوں، دستاویزی پروگرام بھی ہوں، گویا تعلیم وتفریح اور معلومات کو تعمیری اور اخلاقی نقطہ نظر سے ٹی وی اور ریڈیو پرنشر کیا جائے ، اور ایسا کرنا مسلمانوں کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ وہ ہوگا جسے قرآن کریم نے یوں کہا ہے کہ ’’بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں‘‘ (۶)
جنسی بے راہ روی کی تباہ کاریاں
عفت وپاک دامنی کسی بھی قوم اور معاشرے کا طرۂ امتیاز ہے۔ ہر شخص کا اس بات پر یقین ہے کہ عصمت ایک انمول موتی ہے جسے کبھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دفعتا اس حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یا پھر آزادئ نسواں کے علم بردار کارل مارکس اور اینجلز (۷) جیسے گمراہ کرنے والے انسانی درندے اسے رفتہ رفتہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس دور میں عفت وپاک دامنی اپنی قدر وقیمت کھو چکی ہے۔ ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بالخصوص مغرب اس حریم سے بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ ان میں سے اکثر اس نظریہ کے حامی ہو گئے ہیں کہ عورت اور مرد آخر حیوان ہی تو ہیں۔ کیا حیوانوں کے جوڑوں میں نکاح اور وہ بھی دائمی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ (۸) سڑکیں رنڈیوں سے خالی دکھائی دینے لگیں، اس خوف سے نہیں کہ پولیس کے ڈنڈے سے دوچار ہونا پڑے گا بلکہ آزاد خیال بے پردہ گھومنے والی لڑکیوں نے ان کے بازار کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ نشریاتی نظام ہر ملک کا ترجمان ہوتا ہے لیکن جب یورپ میں ایک ستم رسیدہ خاتون اپنے شوہر کی زیادتیوں سے تنگ آ کر وہاں سے حل تلاش کرنے کے لیے مشورہ طلب کرتی ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ۲۸ سال سے قبل تم ایک یا کئی مردوں سے تعلقات قائم کر سکتی ہو۔ کیا اس طرح کے مشورے سے پریشانیوں کا حل نکل سکتا ہے؟
یوں تو عریانیت کے پھیلنے اور زناکاری کے عام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان سب کا احصا طوالت سے خالی نہیں۔ مگر ان میں گندے فوٹو گراف، مخلوط تعلیم، فلم، تھیٹر اور ٹی وی کا اہم رول ہے۔ تعلیمی مراکز جہاں انسانیت کی ذہن سازی کی جاتی ہے، وہیں اس قسم کے جرائم روز افزوں ہیں اور اس کام کے لیے مستقل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس قسم کی تعلیم گاہوں، کالجوں، فرموں کے ٹریننگ اسکول اور مذہبی مدرسوں میں ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ایک ہی صنف کے دو افراد آپس میں شہوانی تعلق رکھتے ہیں۔ (۹) اور جہاں مخلوط تعلیم کا انتظام ہے، وہاں اشتعال اور تسکین قلب دونوں کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مغربی ممالک کے اسکولوں اور دفاتر کے باتھ رومز میں مانع حمل آلات پہلے سے موجود ہوتے ہیں تاکہ تعلیم حاصل کرتے وقت یا کام کرنے کے دوران جنسی جذبات پیدا ہو جائیں تو خواتین وحضرات اور طلبہ وطالبات محفوظ طریقے سے اپنی سفلی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔
جج بن لنڈسے (Ben Lindsey) جنہیں ڈنور کی عدالت جرائم اطفال (Juvenile Court)کے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، انہیں امریکہ کے نوجوانوں کے اخلاقی حالات سے واقف ہونے کا بہت زیادہ موقع ملا۔ انہوں نے اپنی کتاب Revolt of Modern Youth (نوجوان نسل کی بغاوت) میں ایسی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے مغربی نوجوانوں کے اندر سے اخلاقی حس مردہ ہو جانے کا ثبوتملتا ہے۔
امریکہ میں بچے قبل از وقت بالغ ہونے لگے ہیں اور بہت کچی عمر میں ان کے اندر منفی احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے نمونہ کے طور پر ۳۱۲ لڑکیوں کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں ۲۵۵ ایسی تھیں جو گیارہ اور تیرہ برس کے درمیان میں بالغ ہو چکی تھیں اور ان کے اندر ایسی منفی خواہشات اور ایسے جسمانی مطالبات کے آثار پائے جاتے تھے جو ایک ۱۸ برس اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لڑکیوں میں ہونے چاہئیں۔ (۱۰) وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہائی اسکول کی کم عمر لڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ ان کو لڑکوں سے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے، ان میں صرف ۲۵ ایسی تھیں جن کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ باقی میں سے بعض تو اتفاقا بچ گئی تھیں لیکن اکثر کو منع حمل کی موثر تدابیر کا کافی علم تھا۔ یہ واقفیت ان میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں۔ (۱۱) اس کے بعد فاضل مصنف لڑکے اور لڑکیوں کے مابین جنسی خواہشات کا تقابل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہائی اسکول کا لڑکا بمقابلہ ہائی اسکول کی لڑکی کے جذبات کی شدت میں بہت پیچھے ہے۔ عموما لڑکی ہی کسی نہ کسی طرح پیش قدمی کرتی ہے اور لڑکا اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ (۱۲)
۱۹۹۳ء میں امریکی حکومت کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں ایک سال کے اندر ۱۴ لاکھ بارہ ہزار شادیاں قانونی طور پر منعقد ہوئیں۔ ۳ ماہ بعد ہی ان میں سے ۲ لاکھ ۹۲ ہزار کا انجام طلاق پر ہوا۔ تقریبا ۷۵ فی صد شادی شدہ مرد اور خواتین اپنے شریک حیات کے ساتھ بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں جو ان شادیوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے۔ امریکہ کی آبادی میں تقریبا دو کروڑ افراد ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ ۱۶ برس سے لے کر ۱۹ برس تک کی لڑکیاں جنسی حملوں کا نشانہ بنتی ہیں جن میں اکثر اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں یعنی باپ، بھائی وغیرہ کی ہوس کا شکار بنتی ہیں۔ امریکی ہفت روزہ انکوائرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ۱۹۹۹ء میں تقریبا ۹ لاکھ خواتین کی عصمتیں لوٹی گئیں جبکہ ان وارداتوں کے ۶۰ فی صد ملزمان گرفتار بھی نہ ہو سکے۔ (۱۳) روزنامہ جنگ کی اطلاع کے مطابق ہر ۲۷ ویں سیکنڈ میں ایک کم عمر لڑکی ماں بن جاتی ہے۔ ہر ۴۷ویں سیکنڈ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ (۱۴) مسز بل کلنٹن نے ۱۹۹۵ء میں اسلام آباد میں ایک کالج کی طالبات سے گفتگو کے دوران بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نوجوان لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ قانونی طور پر منعقد شادی سے قبل ہی ماں بن جانا ہے۔ (۱۵)
امریکہ کے علاوہ دیگر مغربی ممالک کا بھی یہی حال ہے۔ مثلا برطانیہ میں دس فیصد خاندان بغیر باپ کے پائے جاتے ہیں۔ ۷۰ فی صدلڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جن کو ان کے محبوب یا منگیتر نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہاں میاں بیوی کے تعلقات کچے دھاگوں میں بندھے ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پر طلاق پر منتج ہوتے ہیں۔
آکسفورڈ یونیورسٹی کے ۷۶ فی صد طلبہ وطالبات شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنے کے حق میں ہیں۔ ۲۴ فی صد طالبات نے تسلیم کیا ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد کنواری نہیں رہتیں اور اب بھی ان کے باقاعدہ جنسی تعلقات ہیں۔ ۲۵ فی صد طالبات مانع حمل گولیاں استعمال کرتی ہیں۔ ۲۱ فی صد طلبہ وطالبات فحش وعریاں جرائد خریدتے ہیں۔ ۳۸ فی صد طلبہ وطالبات ہم جنسی کے قائل ہیں۔ (۱۶)
ایک جامعہ کی سروے رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں ۶ ہزار سے زائد بچے جن کی عمر ۱۸ برس سے کم ہے، اپنے علاج، خوراک، رہائش، شراب اور سگریٹ کے حصول کے لیے اپنا جسم فروخت کرتے ہیں جبکہ وہاں کی حکومت ان کو اس حالت زار سے نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ (۱۷)
ایک امریکی جریدہ مغربی ممالک میں اخلاقی حس کے مردہ ہو جانے اور بے حیائی وزنا کاری کے عام ہونے کی وجوہات پر ماتم کرتے ہوئے لکھتا ہے
’’تین شیطانی قوتیں ہیں جن کی تثلیث آج ہماری دنیاپر چھا گئی ہے اور یہ تینوں ایک جہنم تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ فحش لٹریچر جو جنگ عظیم کے بعد سے حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بے شرمی اور کثرت اشاعت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ متحرک تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف بھڑکاتی ہیں بلکہ عملی سبق دیتی ہیں۔ عورتوں کا گرا ہو ااخلاقی معیار جو ان کے لباس اور بسا اوقات ان کی برہنگی اور سگریٹ کے روز افزوں استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کے ہر قید وامتیاز سے ناآشنا اختلاط کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کا نتیجہ مسیحی تہذیب ومعاشرت کا زوال اور آخر کار تباہی ہے۔‘‘ (۱۸)
اسی اخلاقی بگاڑ کو دیکھ کر سیوا سماجی رہنما پاول کہتا ہے: اگر یورپ صرف زنا سے بچ جائے تو اس کے سارے مسائل میں حل کر دوں گا۔ اس سلسلے میں یورپ کے عوام اقدام بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس اخلاقی بگاڑ کا سد باب ہو سکے مگر اب تک خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ مثلا فرانس کی راج دھانی پیرس کے دی پوائنٹ نے ایک سروے کیا تھا جس کی رو سے ۶۸ فی صد شہریوں نے امریکی کلچر کے بڑھتے ہوئے اثرات پر تشویش ظاہر کی تھی اور اسے روکنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ چائنا نے جو امریکہ کی نگاہ میں اسلام کے بعد دوسرا بڑا دشمن ہے، ۱۹۹۷ء میں اپنے مشرقی صوبہ گوانگ ڈونگ میں مغربی فحاشی کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلائی۔ بیس ہزار فحش رسائل اور ۵۶ ہزار گندے کیسٹ ضبط کیے۔ (۱۹)
بے حیائی کی یہ دنیا ہے جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں اور مغرب سے بے حیائی کی ہوا جب چلتی ہے تو سیدھے اسلامی معاشرہ پر آکر تھمتی ہے۔ ان کے اصول زندگی اور عادات واطوار کو قبول کر لینا مسلم معاشرہ میں امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ عمومالڑکیوں کی آخری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ فلم، تھیٹر اور فلم کی زندگی اختیار کر لیں۔ ا س امنگ کی تکمیل کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار رہتی ہیں۔ ان کی ایک خا ص تعداد اپنے آپ کو فلم پروڈیوسرز اور ڈائریکٹروں کی ہوس رانیوں کے حوالے کر کے بے نیل مرام ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کچھ نہیں کرتیں ،آپ سوچ سکتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا (الاحزاب ۳۲) (نرمی سے بات نہ کرو، کہیں وہ لوگ کسی توقع میں مبتلا نہ ہو جائیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ بھلے طریقے سے بات کیا کرو) کیا اسلام اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ لڑکیاں بینکوں کی کلرک، فضائی میزبان، ریستوران میں خدمت گار، مغنیات، رقاصائیں ،فلم، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اداکار بنی ہوئی نظر آئیں؟ ہرگز نہیں۔
لڑکیوں کے سر سے پردہ غائب ہوئے عرصہ ہو گیا۔ اگر کسی کے سر پر دوپٹہ نظر آتا ہے تو بس گلے کی ٹائی کی حد تک۔ جسم پر کپڑے اتنے باریک اور چست ہوتے ہیں کہ جیسے کسی نے تھرمامیٹر سیٹ کر دیا ہو جو جسم کے ہر ظاہری ومخفی حصے کی حرکات وسکنات کا پتہ دیتا ہو۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مغربی ڈرامے کا سین ہمارے سامنے ہے۔ نئے کلچر کے نام پر وحشت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ گھروں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، بازاروں کی رونق بڑھ رہی ہے، پارک آباد ہو رہے ہیں، ہوٹل گھر بن رہے ہیں۔ اکبر کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈرن شرفا کی عمریں ترقی یافتہ ممالک اور ہوٹلوں میں کٹ رہی ہیں۔ وہ مرتے ہیں ہسپتالوں کے بستروں پر، دریا کے کنارے صحت افزا جھونپڑیوں میں اور ریٹ کے بستروں پر بحر محبت موجیں مار رہا ہے اور ساحلوں سے انسانیت کے بکھرے ہوئے اور بچے ہوئے خس وخاشاک بہائے لیے جا رہا ہے۔ یہ صرف آزادئ نسواں کا کرشمہ ہے۔ اب Women's Empowerment کا ہائیڈروجن بم پھٹے گا تو انسانیت کے ذرات فضاؤں میں اڑیں گے جیسا کہ مغربی تہذیب کے تنکے مشرق کے سمعی وبصری ذرائع (Audio Visual Media) پر ٹیلی ویژن اور بھیانک وی سی آر کے ہاتھوں گھر گھر میں اڑ رہے ہیں اور گویا پورا گھر خواب گاہ (Bed Room) بنا ہوا ہے۔ (۲۰)
اجتماع ومعاشرت اور سوشل زندگی میں مغربی طریقوں کی پیروی اور ان کے اصول زندگی اور طرز معاشرت کو قبول کر لینا اسلامی معاشرے میں بڑے دور رس نتائج رکھتا ہے۔ اس وقت مغرب ایک اخلاقی جذام میں مبتلا ہے جس سے اس کا جسم برابر کٹتا اور جلتا چلا جا رہا ہے اور اب اس کا تعفن پورے ماحول میں پھیل چکا ہے۔ اس مرض جذام کا سبب اس کی جنسی بے راہ روی اور اخلاقی انارکی ہے جو بہیمیت وحیوانیت کے حدود تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس کیفیت کا بھی حقیقی اور اولین سبب عورتوں کی حد سے بڑھی ہوئی آزادی، مکمل بے پردگی، مرد وزن کا غیر محدود اختلاط اور شراب نوشی ہے۔ کسی اسلامی ملک میں اگر عورتوں کو ویسی ہی آزادی دی گئی، پردہ یکسر اٹھایا گیا، دونوں صنفوں کے اختلاط کے آزادانہ مواقع فراہم کیے گئے، مخلوط تعلیم جاری کی گئی تو اس کا نتیجہ اخلاقی انتشار اور جنسی انارکی، سول میرج، تمام اخلاقی ودینی حدود واصول سے بغاوت اور بالآخر اس اخلاقی جذام کے سوا کچھ نہیں جو مغرب کو ٹھیک انہی اسباب کی بنا پر لاحق ہو چکا ہے۔ ان اسلامی ملکوں میں جہاں مغربی تہذیب کی پرجوش نقل کی جا رہی ہے اور جہاں پردہ بالکل اٹھ گیا ہے اور مرد وزن کے اختلاط کے آزادانہ مواقع حاصل ہیں، پھر صحافت، سینما، ٹیلی ویژن، لٹریچر اور حکمران طبقہ کی زندگی اس کی ہمت افزائی بلکہ رہنمائی کر رہی ہے، وہاں اس جذام کے آثار وعلامات پوری طرح ظاہر ہونے لگے ہیں اور یہ قانون قدرت ہے جس سے کہیں مفر نہیں۔ (۲۱)
جس معاشرے میں اخلاقی اور سماجی برائیاں ہوں گی، وہ خواہ کتنا ہی دولت مند اور با اثر ہو، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس میں پائیداری نہیں ہوتی کیونکہ معاشرتی اصول ناپید ہوتے ہیں۔ آج کل کے مغربی معاشرے اور سوسائٹی میں اخلاقی اقدار کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے اور معاشرتی وسماجی اصول جو روندے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس قوم کا اخلاق بہت بگڑ چکا ہے۔ اسلام نے چند بنیادی اصول مقرر کر دیے ہیں جن کے اندر رہ کر معاشرہ ترقی پذیر ہو سکتا ہے۔ ان سے باہر نکلنا اخلاق وانسانیت کی موت کے مترادف ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، زناکار مرد اور زناکار عورتوں کے لیے پتھر ہے۔ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، تمہارے حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کے تم پر ۔ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح خدا کی بندیاں ہیں۔ لڑکا اس کا جس کے بستر پر پیدا ہو۔ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے نسبت کرے، اس پر خدا اور رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے۔
مغربی علوم و فنون اور مسلمان
صلیبی جنگوں میں شکست کھانے کے بعد انگریزوں نے اسلامی مصادر کی جڑوں کو متزلزل کرنے کا منصوبہ بنایا اور مسلمانوں کو دین حنیف سے گمراہ کرنے کی بڑے پیمانے پر سازش کی۔ حصول تعلیم کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ سہولت فراہم کر کے مسلم طلبہ کو غلط کیریکٹر اور غیر اسلامی افکار کے حامل بنانے پر زور دیا۔ چنانچہ جو مسلم طلبہ انگریزی جامعات سے تعلیم حاصل کر کے نکلے، ان کے اندر ایمانی بصیرت اور خوف آخرت کا فقدان ہوتا ہے۔ مغربی جامعات میں حصول تعلیم کے بعد جو طلبہ اپنے دین پر اسی طرح قائم رہے جیسا کہ اس دین کا تقاضا ہے تو ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صورت حال ایسی ہو تو اس ترقی کے دور میں جہاں ہر جگہ مغربی طرز تعلیم اور سائنسی اکتشافات کا استقبال کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اس کا جال پھیلا ہوا ہے، ہر میدان میں انہی علوم وفنون کو برتری حاصل ہے، اس کی سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ گھنٹوں کے مشکل کام کو منٹوں میں آسان بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟ ان علوم وفنون اور سہولیات سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانا چاہئے کہ نہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمان ابھی مغربی تعلیم ونظریات کو جوں کا توں قبول کر لے، اس صورت میں اس تعلیم کے جو نتائج اذہان وقلوب اور معاشرے پر منتج ہوں گے، وہ محتاج بیان نہیں۔ سابقہ بیان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مغربی طرز تعلیم اور سائنسی اکتشافات وایجادات کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ اس صورت میں مسلمان اپنے منصب پر قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے خیر امت کے نام سے خطاب کیا ہے اور پھر مسلمان ایسی صورت میں اپنی ضرورت کو حل کیسے کریں گے؟ جبکہ ہمارے دینی جامعات میں ان علوم وفنون کے حصول کا انتظام کالعدم ہے۔ وہاں جن علوم پر زور دیاجاتا ہے، معاصرزمانہ کے تحت ہمارے ضرورت کے حل کے لیے ناکافی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پیچیدگی کا حل مفتی محمد ظفیر الدین صاحب مفتی دار العلوم دیوبند کے اس بیان سے نکالا جا سکتا ہے۔
’’اگر مدارس دینیہ میں نئے اکتشافات اور جدید ایجادات کی تعلیم نہیں دی جاتی، اگر سائنس نہیں پڑھائی جاتی، یا سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے دوسرے کام نہیں ہو سکتے تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ان میں ہمارے نوجوان علما باکمال ہوں۔ اسی کے ساتھ مدارس کو جس حد تک حالات وزمانہ کے مطابق آگے لے جایا جا سکتا ہے، لے جانا چاہئے۔ نئے زمانہ کی اچھی چیزوں کو خوش آمدید کہنا اور اپنانا گناہ نہیں، کار ثواب ہے۔ یہ مسلمانوں کی گم شدہ متاع ہے، جہاں بھی مل جائے لے لینی چاہئے۔ ا س پر بدعت کا حکم لگا کر کنارہ کش ہونا دانش مندی نہیں۔ خوب یاد رکھا جائے اچھی چیزوں کو اپنانا ترکہ ہے، سرقہ نہیں۔‘‘ (۲۲)
یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ سائنسی علوم وفنون اور ایجادات کو مغربی اثاثہ قرار دیتے ہیں جب کہ یہ مسلم دانش وروں اور سائنس دانوں کی میراث ہے جس سے مسلمانوں نے مدت العمر تک لاپروائی برتی، خالی میدان دیکھ کر اہل مغرب آ دھمکے اور اسے اچک لیا اور مسلمانوں کو اپنا دست نگر بنا دیا۔ اگر ہم اسلام کے اصول پر قائم رہ کر حصول علم اور تحقیق کا فریضہ ادا کرتے تو آج ہمیں جدید علوم وفنون کے لیے یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی حالانکہ قرآن نے لعکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تشعرونکے الفاظ استعمال کر کے مسلمانوں کو سائنسی علوم کے حصول کی طرف ابھارا ہے، جیسا کہ علامہ اسد لکھتے ہیں
’’تاریخ سے بلا کسی اشتباہ کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے سائنسی ترقی کو جتنا ابھارا ہے، اتنا کبھی کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ اسلامی دینیات سے علوم وفنون اور سائنسی تحقیق کی جو ہمت افزائی ہوئی، اس کا نتیجہ بنو امیہ اور بنو عباس اور ہسپانیہ کی عرب حکومت کے دور کی شاندار تہذیبی ترقیوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔‘‘ (۲۳)
دوسری شق کا جواب ہمیں حضور ﷺ کے اس حکم سے مل جاتا ہے کہ آپ نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ کو کسی خاص مقصد کے تحت یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دینی جامعات میں بھی دیگر فنون کی طرح ایک شعبہ انگریزی زبان وادب کی افہام وتفہیم کے لیے قائم کر کے مسلم طلبا کو انگریزی زبان وادب کا ماہر بنایا جائے۔ اس طرح ضرورت کی تکمیل ہو سکتی ہے اور خیر امت کا فریضہ بھی انجام پا سکتا ہے۔ بقول سرسید
’’مسلمانوں کی تعلیم کا طریقہ دو قسم کا ہونا چاہئے۔ ایک وہ جس کو مسلمان خود قائم کریں جس سے ان کے تمام دینی ودنیاوی مقاصد انجام پائیں۔ دوسرے وہ جس سے مسلمان ان اصول سے جو گورنمنٹ نے قائم کیے ، فائدہ اٹھائیں‘‘ (۲۴)
اب رہا مسئلہ عام اسکولوں کی تعلیم کا جو مسلمانوں کی نگرانی میں چلتے ہیں، جہاں دینیات کی تعلیم کا فقدان اور تربیت اسلامی کا معقول انتظام نہیں ہے اور سارا زور معاصر زمانہ علوم پر ہی دیا جاتا ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے نہ کہ معاصر زمانہ تعلیم کی خرابی۔ اس سلسلے میں یہ حدیث پیش کرنے کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یھودانہ وینصرانہ ویمجسانہ (۲۵) (ہر بچہ خالص فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں) اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر انگریزی تعلیم کے فوائد ونقصانات سے متعلق مزید باتیں سوچی جا سکتی ہیں۔
حواشی
(۱) اسلام اکیسویں صدی میں‘ ص ۳۳
(۲) مغربی تمدن کی جھلک‘ ص ۴۴
(۳) ماہنامہ الحق‘ اکوڑہ خٹک
(۴ و۵) ذرائع ابلاغ اور اسلام‘ بحوالہ معرکہ اسلام اور جاہلیت‘ مولانا صدر الدین اصلاحی‘ ص ۲۰۳
(۶) ماہنامہ ترجمان القرآن‘ لاہور‘ اگست ۲۰۰۰‘ ص ۶۸
(۷) اسلام ایک نظریہ ایک تحریک‘ مریم جمیلہ۔ مترجم‘ آماد شاہ پوری‘ ص ۳۰۷
(۸ و۹) پردہ‘ سید ابو الاعلی مودودی‘ ص ۴۷
(۱۰) سنت نبوی اور جدید سائنس‘ حکیم طارق محمود چغتائی‘ ج ۱‘ ص ۳۰۷
(۱۱) پردہ ‘ سید مودودی
(۱۲) سنت نبوی اور جدید سائنس‘ ج ۱ ‘ ص ۳۰۱
(۱۳) ہفت روزہ اکانومسٹ‘ اکتوبر ۱۹۹۴ء‘ بحوالہ ترجمان القرآن‘ مئی ۲۰۰۰ء
(۱۴) رو زنامہ جنگ لندن‘ ۲۸ اپریل ۱۹۸۷ء۔ بحوالہ سنت نبوی اور جدید سائنس ج ۲‘ ص ۶۵
(۱۵)ایضا‘ ۲۵ مارچ ۱۹۹۵ء‘ بحوالہ ترجمان القرآن لاہور‘ مئی ۲۰۰۰ء
(۱۶) ایضا‘ ۵ مارچ ۱۹۹۰ء‘ بحوالہ سنت نبوی اور جدید سائنس‘ ج ۲‘ ص ۶۴
(۱۷) روزنامہ نوائے وقت‘ ۴ جنوری ۲۰۰۰ء
(۱۸) پردہ‘ سید مودودی
(۱۹) اسلام اکیسویں صدی میں‘ ص ۳۷‘ ۳۸
(۲۰) ترجمان القرآن‘ اپریل ۲۰۰۰‘ ص ۴۹
(۲۱) مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی کشمکش‘ ابو الحسن علی ندوی‘ ص ۲۳۹
(۲۲) ماہنامہ ارمغان‘ دعوت اسلام نمبر‘ جنوری فروری مارچ ۱۹۹۸ء‘ ص ۱۱۹
(۲۳) اسلام دوراہے پر‘ ص ۶۳
(۲۴) حیات جاوید‘ الطاف حسین حالی
(۲۵) بخاری شریف‘ باب ما قیل فی اولاد المسلمین‘ ص ۱۸۵‘ کتب خانہ رشیدیہ دہلی
(بشکریہ ماہنامہ دار العلوم دیوبند، انڈیا)
پاکستان شریعت کونسل کے راہ نماؤں کا دورۂ قندھار
ادارہ
پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی اور سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی نے عید الاضحی کے بعد مولانا رشید احمد درخواستی کے ہمراہ قندھار کا تین روزہ دورہ کیا اور امیر المومنین ملا محمد عمر حفظہ اللہ تعالی سے ملاقات کر کے انہیں نفاذ اسلام کے اقدامات اور بت شکنی پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے امارت اسلامی افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مولانا فداء الرحمن درخواستی نے جامعہ انوار القرآن آدم ٹاؤن کراچی اور پاکستان شریعت کونسل کی طرف سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا عطیہ بھی طالبان حکومت کی امداد کے لیے پیش کیا۔ پاکستان شریعت کونسل کے راہ نماؤں نے افغانستان کے قاضی القضاۃ مولوی نور محمد ثاقب اور قندھار کے کور کمانڈر ملا اختر محمد عثمانی سے ملاقات کی اور ان سے افغانستان کی تازہ ترین صورت حال پر تبادلہ خیالات کیا۔ کراچی میں امارت اسلامی افغانستان کے قونصل جنرل ملا رحمت اللہ کاکا زادہ قندھار سے واپسی پر ان کے رفیق سفر تھے اور ان سے افغانستان پر اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے اثرات اور طالبان حکومت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی نے اس موقع پر کہا کہ افغانستان پر اقوام متحدہ کی پابندیاں سراسر ظالمانہ اور جانبدارانہ ہیں جن کے خلاف تمام مسلم ممالک کو صدائے احتجاج بلند کرنی چاہئے۔ انہوں نے کہاکہ ملی غیرت کا تقاضا ہے کہ تمام مسلم حکومتیں طالبان حکومت کو تسلیم کر کے اقوام متحدہ کی پابندیوں کو مسترد کریں اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے اس سے بھرپور تعاون کریں۔انہوں نے کہا کہ بے جان مجسموں کو مسمار کرنے پر دنیا بھر کے واویلا سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ آج کے عالمی نظام اور بین الاقوامی رائے عامہ کو زندہ انسانوں اور ان کی مشکلات وتکالیف سے کوئی دل چسپی نہیں ہے اور بے جان بتوں کو بچانے کے لیے سب لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کے اس اقدام نے عالمی برادری کے منافقانہ طرز عمل اور ورلڈ سسٹم کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کر دیا ہے۔
مولانا راشدی کا دورۂ پشاور
پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی نے گزشتہ ہفتے پشاور کا مختصر دورہ کیا اور پاکستان شریعت کونسل صوبہ سرحد کے امیر مولانا میاں عصمت شاہ کاکاخیل کو دورۂ قندھار کے تاثرات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ صوبہ سرحد میں کونسل کی رابطہ مہم کے سلسلے میں ان سے تبادلہ خیال کیا۔
مرکزی راہ نماؤں کا دورۂ کوئٹہ
پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا فداء الرحمن درخواستی اور سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی نے قندھار سے واپسی پر کوئٹہ میں ایک روز قیام کیا اور پاکستان شریعت کونسل صوبہ بلوچستان کے کنوینر مولانا محمد حسن کاکڑ اور دیگر راہ نماؤں سے ملاقات کر کے انہیں دورۂ قندھا رکے تاثرات سے آگاہ کرنے کے علاوہ ان سے مختلف امور پر گفتگو کی۔
صوبہ سندھ کے نئے عہدے دار
پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی نے صوبہ سندھ کے لیے کونسل کے مندرجہ ذیل نئے عہدے داروں کا اعلان کیا ہے اور انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ باہمی مشورے سے باقی عہدے داروں کا انتخاب کر لیں
امیر — مولانا عبد الرشید انصاری — کراچی
سیکرٹری جنرل — مولانا سیف الرحمن ارائیں — حیدر آباد
رابطہ سیکرٹری — مولانا قطب الدین انصاری — حیدر آباد
سیکرٹری اطلاعات — مولانا رشید احمد درخواستی — کراچی
خدمات دار العلوم دیوبند کی حمایت
پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی نے جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام ۹، ۱۰، ۱۱ اپریل ۲۰۰۱ء کو پشاور میں منعقد ہونے والی ’’عالمی خدمات دار العلوم دیوبند کانفرنس‘‘ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے پاکستان شریعت کونسل کے تمام عہدہ داروں اور ارکان سے کہا ہے کہ وہ کانفرنس میں شریک ہوں اور اسے کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعاون کریں۔ دریں اثنا کانفرنس کے داعی اور جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمن نے گزشتہ ہفتے گوجرانوالہ میں پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی سے ملاقات کر کے انہیں کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی ہے اور وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولانا صلاح الدین فاروقی اور صوبہ سرحد کے امیر مولانا میاں عصمت شاہ کاکاخیل کے ہمراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔
علما کی اندھا دھند گرفتاریوں پر احتجاج
پاکستان شریعت کونسل صوبہ پنجاب کے سیکرٹری جنرل مولانا قاری جمیل الرحمن اختر نے محرم الحرام کے موقع پر ملک بھر میں علماء کرام اور دینی کارکنوں کی اندھا دھند گرفتاریوں پر شدید احتجاج کیا ہے اور ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت فرقہ وارانہ بد امنی کے اصل اسباب وعوامل کو دور کرنے کے بجائے ہر سال محرم الحرام کے موقع پر بلا جواز گرفتاریوں اور پابندیوں کے ذریعے سے وقت گزارنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے صورت حال بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن علما کی گرفتاری، ضلع بندی اور زبان بندی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان میں سے بہت سے حضرات کئی سال پہلے وفات پا چکے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان گرفتاریوں اور پابندیوں کا مقصد صرف کارروائی ڈالنا اور رسم پوری کرنا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرز عمل پر نظر ثانی کی جائے اور گرفتاریوں اور پابندیوں کے احکام واپس لے کرفرقہ وارانہ کشیدگی اور بد امنی کے اسباب وعوامل کی نشان دہی کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔
مرکزی مجلس شوری کا اجلاس
پاکستان شریعت کونسل کی مرکزی مجلس شوری کا ایک اہم اجلاس ۲۹ اپریل ۲۰۰۱ء بروز اتوار صبح دس بجے الشریعہ اکادمی کنگنی والا گوجرانوالہ میں امیر مرکزیہ حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی کی زیر صدارت منعقد ہوگا جس میں نفاذ شریعت کی جدوجہد کے حوالے سے رابطہ مہم کو تیز کرنے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد ۳ بجے دن الشریعہ اکادمی میں پاکستان شریعت کونسل کے زیر اہتمام علماء کرام اور دینی کارکنوں کے لیے ایک خصوصی نشست بھی ہوگی جس سے حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی اور حضرت مولانا زاہد الراشدی موجودہ عالمی اور ملکی صورت حال کے تناظر میں علماء کرام اور دینی جماعتوں کی ذمہ داریوں کے موضوع پر تفصیلی خطاب کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’آدابِ حاملینِ قرآن‘‘
قرآن کریم کے آداب و فضائل اور حفاظ و قراء کے لیے ضروری ہدایات کے حوالے سے معروف محدث امام شرف الدین نوویؒ شارح مسلم کی کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن کا اردو ترجمہ حضرت مولانا نجم الدین اصلاحیؒ نے کیا تھا جو بھارت میں شائع ہو چکا ہے اور اب اسے مکہ کتاب گھر، الکریم مارکیٹ، اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے۔ صفحات ۱۲۰، کتابت و طباعت مناسب، مضبوط جلد، قیمت ۶۳ روپے۔
’’محمد ﷺ اور قرآن‘‘
سلمان رشدی کی رسوائے زمانہ تصنیف ’’شیطانی آیات‘‘ میں جناب نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی اور حضرت صحابہ کرام و ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کے بارے میں اہانت آمیز اور گستاخانہ طرز بیان اور مواد پر ایک عرصہ سے دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ بھارت کے معروف دانش ور ڈاکٹر رفیق زکریا نے سلمان رشدی کی اس خرافات کا قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں محققانہ جائزہ لیا ہے اور ۴۳۲ صفحات پر مشتمل اس ضخیم تصنیف میں ان تمام واقعات کا احاطہ کیا ہے جن کے بارے میں سلمان رشدی نے ہرزہ سرائی کی ہے۔
یہ کتاب فکشن ہاؤس، ۱۸ مزنگ روڈ، لاہور نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت ۲۰۰ روپے ہے۔
’’ردِ قادیانیت کے زریں اصول‘‘
حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی ایک عرصہ سے علماء اور طلبہ کو قادیانیت کے موضوع پر لیکچر دے رہے ہیں اور عقیدۂ ختم نبوت، حیات عیسی علیہ السلام، امام مہدی کی علامات، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی کی حقیقت پر قادیانیوں کے پرفریب دلائل کی اصلیت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ۱۹۹۰ء میں انہوں نے دار العلوم دیوبند میں علماء اور طلبہ کو ان موضوعات پر جو لیکچر دیے، انہیں کتابی شکل میں مرتب کیا گیا ہے اور حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود کے وقیع مقدمہ نے اس کی افادیت کو دوچند کر دیا ہے۔ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے علماء، طلبہ اور دینی کارکنوں کے لیے یہ بیش بہا تحفہ ہے۔
۴۴۰ صفحات پر مشتمل اس مجلد کتاب کی قیمت ۱۵۰ روپے ہے اور اسے ادارہ مرکز دعوت و ارشاد چنیوٹ ضلع جھنگ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
’’قافلہ ادبِ اسلامی‘‘
مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ کے علمی آثار اور صدقات جاریہ میں ادب اسلامی کے حوالے سے قائم ہونے والا عالمی فورم ’’عالمی رابطہ ادب اسلامی‘‘ بھی ہے جو ان کی سرپرستی میں وجود میں آیا اور پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں اس کی شاخیں کام کر رہی ہیں۔ عالمی رابطہ ادب اسلامی کی پاکستان شاخ نے ادب اسلامی کے فروغ کے لیے ’’قافلہ ادب اسلامی‘‘ کے نام سے ایک سہ ماہی مجلہ کی اشاعت کا آغاز کیا ہے جو عربی، اردو اور انگلش تین زبانوں میں ہے اور معروف دانش ور ڈاکٹر ظہور احمد اظہر اس کے مدیر ہیں۔
زیر نظر شمارہ پہلی جلد کا شمارہ نمبر ۳، ۴ ہے جو دو سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی قیمت ۱۰۰ روپے ہے۔ ملنے کا پتہ:۷ حق باہو ہاؤسز، لالہ زار کالونی، رائے ونڈ، لاہور
’’برکاتِ وضو‘‘
عارف باللہ حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی رحمہ اللہ تعالی نے اس مضمون میں وضو کی برکات و فضائل جناب نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں تحریر فرمائے ہیں ۔
۲۸ صفحات پر مشتمل یہ مضمون دار الارشاد، خانقاہ مدنی، اٹک شہر نے شائع کیا ہے جس کا ہدیہ ۱۰ روپے ہے۔
دسمبر ۲۰۰۱ء
افغانستان اور موجودہ عالمی صورت حال
ادارہ
(افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے خیالات آئندہ شمارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ سردست موقر قومی روزنامہ نوائے وقت کا ۲۹ نومبر ۲۰۰۱ء کا اداریہ اور ادارتی شذرات قارئین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جن میں موجودہ صورتِ حال اور مستقبل کے خدشات وتوقعات کی بہت بہتر انداز میں عکاسی کی گئی ہے اور ہمیں بھی ’’نوائے وقت‘‘ کے اس حقیقت پسندانہ تجزیے سے اتفاق ہے۔ رئیس التحریر)
افغان بحران میں حکومت پاکستان نے امریکہ سے جو توقعات وابستہ کی تھیں، وہ نقش بر آب ثابت ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ حالات جو رخ اختیار کر رہے ہیں، وہ نہ صرف کشمیری عوام کی جدوجہد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں بلکہ ہمارے ایٹمی سائنس دانوں کے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے علاوہ ایران سے رابطوں کا ہوّا کھڑا کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے تعاون کا فیصلہ کرتے وقت واضح کیا تھا کہ وہ نہ تو شمالی اتحاد کا کابل پر قبضہ برداشت کرے گا اور نہ جنگ کی طوالت کے حق میں ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی اور جہاد میں فرق ملحوظ رکھنے کی بات بھی کی اور سٹرٹیجک اثاثوں کے تحفظ کے لیے قوم کو امریکی حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی مگر کابل پر شمالی اتحاد کے قبضے، جنگ کو مقاصد کے حصول تک جاری رکھنے بلکہ اس کا دائرہ دوسرے ممالک تک وسیع کرنے کے اعلانات سے واضح ہو گیا ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی اور ۱۱ ستمبر سے پہلے کی طرح ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتے۔
اپنے ہی دوست طالبان کے خلاف جنگ میں ثبوت حاصل کیے بغیر امریکہ کا ساتھ دے کر ہم نہ صرف اقتصادی اور معاشی مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں بلکہ سیاسی، عسکری اور معاشرتی مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی کسی واضح جہت سے محروم ہو گئی ہے اور ہم دوستوں کے حلقے سے نکل کر دشمنوں کے محاصرے میں آ گئے ہیں۔ ہماری مشرقی سرحدیں ہمیشہ سے غیر محفوظ چلی آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ایک بڑی، طاقتور، جدید ہتھیاروں سے مسلح اور تربیت یافتہ فوج کی ضرورت لاحق ہے۔ اس کے علاوہ وسائل کا بڑا حصہ اپنے دفاع اور سلامتی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختص کرنا پڑتا ہے۔ امریکی دباؤ اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اب ہم نے شمال مشرقی سرحد بھی غیر محفوظ کر لی ہے اور فوج کا اچھا خاصا حصہ حکومت کو افغان سرحد پر متعین کرنا پڑ رہا ہے۔ جغرافیائی گہرائی کا جو تصور قوم کو دیا گیا تھا، وہ پاش پاش ہو گیا ہے اور امریکہ کے اس اعلان کے بعد کہ وہ نہ صرف افغانستان میں اڈے قائم کرے گا بلکہ علاقے میں طویل عرصے تک موجود رہ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، علاقائی صورت حال میں بھی تبدیلی آ رہی ہے جو ہمارے قومی مفادات سے سراسر متصادم ہے۔
امریکہ کی ترجیح اول بھارت ہے جو ایک بڑی تجارتی منڈی، دفاعی پارٹنر اور مادر پدر آزاد مغربی تہذیب سے ہم آہنگی کی بنا پر امریکہ ومغرب کے لیے زیادہ قابل قبول ہے۔ بھارت کے مشورے پر امریکہ نے شمالی اتحاد کی سرپرستی کی اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی۔ بھارت اسرائیل گہرے روابط بھی امریکہ کے جھکاؤ میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور اب شمالی اتحاد کے سرپرست کے طور پر بھارت کابل میں اپنی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ ہمارا ایٹمی پروگرام اور عالم اسلام سے تعلقات بھی امریکہ کی نظروں میں کھٹکتے ہیں اور وہ یہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ ۱۱ ستمبر تک ہم طالبان کے قریبی ساتھی اور سرپرست تھے۔ چینی وزیر اعظم کی پاکستان آمد کے موقع پر دونوں ممالک میں گوادر کی بندرگاہ اور مکران کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا جو معاہدہ ہوا، وہ ہر لحاظ سے سنگ میل تھا اور یہ امریکہ وروس کی دیرینہ خواہشوں کے علی الرغم تھا جو گوادر اور بلوچستان کے وسیع ساحل تک رسائی کے لیے ایک عرصہ سے خواہاں تھے۔ ہم نے اسی وقت لکھا تھا کہ امریکہ کو یہ معاہدہ مشکل سے ہی ہضم ہوگا۔
اس سمجھوتے سے ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ امریکہ پر مزید انحصار نہیں کیا جا سکتا اسی لیے ہم نے چین سے تعلقات کے نئے دور کا آغاز کیا ہے لیکن ۱۱ ستمبر کے بعد اچانک یوٹرن لے کر ہم ایک بار پھر امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے ہیں اور اگر ہماری اس حماقت کی وجہ سے امریکہ علاقے میں مستقل اڈے قائم کر لیتا ہے تو ہمارے علاوہ چین اور ایران کے مفادات کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور یہ چیز ہمارے علاوہ چین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ماضی میں چین ہمیں دفاع اور سلامتی کے معاہدے کی پیشکش کر چکا ہے جس سے ہم امریکی خوف کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اب یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم پاک چین تعلقات کو مزید نقصان سے بچانے اور اپنے مستقبل کے علاوہ مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے چین کی موجودہ ناراضگی دور کریں اور وہ رشتے مضبوط بنائیں جن کا ماضی میں دونوں طرف سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔
ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اس دوستی میں امریکہ کی ریشہ دوانیوں سے پڑنے والی دراڑوں کو بھرنے اور قد آور درخت سے مرجھاتے ہوئے اس پودے کو تازہ آب وہوا فراہم کرنے کے لیے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا اہم عنصر امریکہ کے بجائے چین ہے اور دونوں ممالک کا مفاد مشترک ہے کیونکہ امریکہ بھارت اور ایک لحاظ سے روس کے ذریعے سے دونوں کے لیے خطرات میں اضافہ کر رہا ہے۔ افغانستان میں عدم استحکام اور امریکہ وروس اور ان کے مشترکہ دوست بھارت کی مداخلت یا باہمی مفادات کے ٹکراؤ کی صورت میں کشمکش کے اثرات پاکستان اور چین پر یکساں مرتب ہوں گے اور جس جہاد کے خاتمے کے لیے امریکہ اتنی دور سے وارد ہوا ہے، وہ بھی جلدی ختم ہونے والا نہیں کیونکہ جس طرح ڈینگ سیاؤپنگ کی اصلاحی اور اعتدال پسندانہ پالیسیوں کے باوجود چین کمیونزم اور سوشلزم کو ترک کرنے پر تیار نہیں اور وقتاً فوقتاً اس نظریے سے وابستگی کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے، اسی طرح کوئی مسلمان بھی جہاد سے دامن چھڑا کر اپنے خدا اور رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کرتا اور پاکستان فوج کا تو ماٹو ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے یا تبدیل ہو چکا ہے؟
اہل پاکستان اور مسلمانوں نے چین کا کمیونزم برداشت کیا ہے تو چین کو بھی جہاد سے الرجک نہیں ہونا چاہیے البتہ سنکیانگ اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے سے گریز کریں جو چین کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے انہیں اکساتا رہتا ہے اور الزام پاکستان یا افغانستان پردھر دیا جاتا ہے۔ ہم ان کے معاملات میں دخل نہ دیں اور کوشش کریں کہ چینی حکومت اور مسلمانوں میں افہام وتفہیم ہو تاکہ کسی غلط فہمی کا امکان باقی نہ رہے۔ اس طرح ہم چین کے ساتھ مل کر کوئی طویل المیعاد منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور دفاع وسلامتی کو درپیش نئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ گوادر بندرگاہ، مکران ساحلی ہائی وے کے علاوہ شاہراہ ریشم کے ذریعے سے نہ صرف رشتوں کو مضبوط بلکہ معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ عوام تو پہلے سے جانتے ہیں لیکن حکمرانوں پر بھی جلد واضح ہو جائے گا کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں اس لیے مزید اس کے جال میں پھنسے رہنا دانش مندی نہیں۔ جب بحران کے دوران میں وہ ہماری کوئی بات ماننے پر تیار نہیں اور ہمارے مفادات کے منافی اقدامات میں مصروف ہے تو بعد از جنگ حکمت عملی سے کسی قسم کی توقع وابستہ کرنا خوش فہمی ہے جس کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔
مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف ایکشن
پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے گزشتہ روز بلوچستان سے منتخب ہونے والے ضلعی ناظمین سے بات چیت کے دوران میں کہا ہے کہ انتہا پسندوں کے خلاف ایکشن کا اعلان چند روز تک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چند مذہبی انتہا پسندوں کو ۱۴ کروڑ عوام کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہا پسندی جس معاشرے میں جڑ پکڑ لے، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کون تنگ نظر ہے اور کون نہیں، آسان نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی تنگ نظر کے نقطہ نظر کو دوسرا شخص تسلیم نہ کرے تو وہ اس پر انتہا پسندی کی تہمت لگا کر اسے قومی مجرم قرار دے دیتا ہے۔
صدر جنرل پرویز مشرف اس وقت حکمران وقت ہیں اور ایسے حکمران ہیں جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اختیارات کے سرچشمے ان کی ذات گرامی سے پھوٹتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ان کا ایک عوامی چہرہ بھی ہے جسے ایک سیاست دان کا چہرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اپنے اس روپ میں انہیں سیاست دانوں اور بالخصو ص مذہبی راہنماؤں کے بارے میں رائے دیتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی راہنماؤں کا اپنا ایک مخصوص کردار ہے اور عوام انہیں عقیدت واحترام سے دیکھتے ہیں۔ عقیدت کے ان آبگینوں کی شکستگی ان کے لیے سوہانِ روح ہوتی ہے خصوصاً اس صورت میں جب ان کی حب الوطنی شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمن اور مولانا سمیع الحق کی نظر بندی سیاسی وجوہ کی بنا پر ہے۔ ان کے سیاسی بیانات ان کی اپنی جماعت اور سیاسی نظریات کے نقیب ہیں اور انہیں انتہا پسندی شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم یہ بات بھی واضح ہے کہ افغانستان پر امریکہ کی بے تحاشا بمباری اور معصوم مردوں، عورتوں ، بوڑھوں اور بچوں کے قتل عام نے پاکستان کے مسلمانوں میں انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا کیے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ آرا جنرل مشرف کی حکمت خارجہ اور امریکہ دوستی کے مطابق نہ ہوں لیکن اس اختلاف رائے کے تحت معاشرے کے کسی طبقے پر کریک ڈاؤن کرنا قرین مصلحت نہیں۔ پاکستان کو اس وقت انتشار کے بجائے قومی یک جہتی، تنگ نظری کے بجائے کشادہ نظری اور انتہا پسندی کے بجائے عالی ظرفی کی ضرورت ہے لیکن اس کا مظاہرہ بالائی سطح سے حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ حکومت نے جس طرح کریک ڈاؤن کا ارادہ ظاہر کیا ہے، وہ موجودہ حالات میں ہمارے داخلی مفادات کے مطابق نہیں ہے۔ بنیادی جمہوریتوں کے تحت جو ضلعی ناظمین منتخب ہو کر برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے ابھی تک کسی قسم کے سیاسی شعور اور سماجی آگہی کا ثبوت نہیں دیا۔ انہیں اس مشکل میں الجھانا ہرگز مناسب نظر نہیں آتا۔
عرب دنیا میں اسلامی حمیت کی تازہ لہر
سعودی عرب نے دہشت گردی سے مبینہ طور پر منسلک گروپوں کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے امریکی درخواست کو رد کر دیا ہے۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ وہ بغیرثبوت کے کارروائی نہیں کر سکتے، امریکی ثبوت ناکافی ہیں۔جبکہ شہزادہ سلطان نے خیال ظاہر کیا ہے کہ افغان جنگ کسی بھی کروٹ بیٹھے، ہمارا موقف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ ثبوت کے بغیر کسی عرب یا مسلمان کو مورد الزام ٹھہرانا حق وانصاف کے خلاف ہے۔ عرب لیگ نے بھی اپنی دو روزہ کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو وہ مخالفت کرے گی۔یوں لگتا ہے کہ افغانستان پر حملے کی آڑ میں جس مختلف النوع انداز سے امریکہ پوری دنیا میں اسلام اورمسلمانوں پر حملہ آور ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ بتدریج مسلم امہ میں بیداری اور اسلامی حمیت کی ایک لہر سی اٹھی ہے۔
سعودی عرب وہ واحد عرب ملک ہے جس کے باشندوں کی تذلیل وتوہین مغربی میڈیا پر سب سے بڑھ کر کی جا رہی ہے، اگرچہ سعودی عرب عسکری لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں اور نہ اس کے پاس ایٹمی اسلحہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس نے دہشت گردی سے مبینہ طور پر منسلک گروپوں کے اثاثے منجمد کرنے سے صاف انکار کر کے جرات مندانہ اقدام کیا ہے۔ شاید سعودی حکمرانوں نے بالآخر امریکی تیور بھانپ کر ہی یہ فیصلہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ بش انتظامیہ فوری طور پر بات چیت کے لیے وزارت دفاع، خزانہ اور قومی سلامتی کونسل کے حکام پر مشتمل ایک وفد سعودی عرب روانہ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ سعودی حکمرانوں پر اس وفد کے ذریعے سے عملی تعاون کے لیے دباؤ ڈالے گا لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ شاید اب سعودی حکومت اس سلسلے میں امریکہ کی تابع داری کے اثر سے نکل آئے گی۔ جس طرح عرب لیگ نے بھی اپنی کانفرنس میں ٹی وی چینل اور عرب رابطہ قائم کرنے کے ساتھ عراق پر ممکنہ حملے کی صورت میں اپنی مخالفت کا عندیہ ظاہر کر دیا ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عرب ملت اجتماعی لحاظ سے اب اس دام ہم رنگ زمین سے آگاہ ہو گئی ہے جو جگہ جگہ عالم عرب میں امریکہ نے پھیلا رکھا ہے۔ بہرصورت اب عراق جو ایک عرب ملک ہے تو عرب لیگ کی رگ حمیت پھڑکی ہے۔ خدا کرے کہ عرب خود کو بھی امریکہ کے حصار سے نکال لیں، غنیمت ہوگا۔ ابھی تو شاید یہ ممکن نہ ہو لیکن جلد ہی آنے والا وقت بتائے گا کہ اگر مسلم امہ طالبان کو اپنے ایک پیشگی دفاع کے طور پر مضبوط کرتی اور انہیں تنہا امریکی بموں کا ایندھن نہ بننے دیتی تومسلمان دشمنی کی صلیبی آگ افغانستان میں ہی بھسم ہو جاتی اور اس کے شعلے یہاں سے ہو کر ملت بیضا کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ملکوں تک پہنچنے کا خطرہ پیدا نہ ہوتا۔ ہم پر امید ہیں کہ شاید طالبان کی قربانیاں قبول ہو جائیں اور عالم اسلام صلیبیوں کے ہاتھوں اپنی اجتماعی بربادی سے بچ جائے۔
بیعت کی حقیقت اور آداب
مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے ایک بیعت اسلام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں لوگ یہی بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ دوسری بیعت ہجرت کے لیے ہوتی تھی۔ لوگ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر جانے کی بیعت یا عہد کرتے تھے۔ تیسری بیعتِ جہاد تھی۔ جب جنگ کا موقع آتا تھا تو لوگ اس بات کی بیعت کرتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں جان ومال کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بعض صحابہؓ نے ارکان اسلام پر پابندی کی بیعت کی۔ حضرت جریرؓ کی بیعت اسی سلسلے میں تھی کہ میں ارکان اسلام نماز، روزہ، حج، زکٰوۃ وغیرہ کی پابندی کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کروں گا۔ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر اس بات کی بیعت بھی کی کہ وہ سنت پر قائم رہیں گے اور بدعات سے بچتے رہیں گے۔ پھر عورتوں نے بھی اس بات کی بیعت کی کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھیں گی (یعنی غیر کی اولاد کو خاوند کی طرف منسوب نہیں کریں گی) اور نہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ اس بیعت کا ذکر سورۃ الممتحنہ میں موجود ہے۔ بیعت کی ایک قسم بیعتِ تبرک بھی ہے۔ حضرت زبیرؓ اپنے آٹھ سال کے بیٹے حضرت عبد اللہؓ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرایا۔ یہ یہی بیعت تھی ورنہ بچے کے لیے بیعت کی ضرورت نہ تھی۔
ایک بیعتِ خلافت بھی ہوتی ہے جو خلیفہ کے انتخاب کے لیے ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور اسی طرح دیگر خلفائے راشدینؓ کی بیعت بھی ہوئی۔
بعض اوقات بزرگان دین کے کسی سلسلے میں داخل ہونے کے لیے بیعتِ سلوک بھی کی جاتی ہے ۔ اس کا مطلب یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کہ ہم ارکانِ دین کی پابندی کریں گے، عبادت وریاضت اور ذکر واذکار باقاعدگی سے انجام دیں گے تاکہ درجاتِ عالیہ نصیب ہوں اور اللہ کا تقرب حاصل ہو سکے۔ بیعت کی یہ تمام قسمیں حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں۔
شاہ رفیع الدینؒ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کسی بزرگ کے ہاتھ پر محض دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی بیعت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارا کوئی معاملہ سلجھا دیں گے یا ہماری سفارش کر دیں گے۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہ رسمی بیعت ہے جس کا کچھ فائدہ نہیں۔ البتہ بیعت کی باقی جتنی اقسام بیان کی گئیں، وہ درست ہیں۔
پیر کے اوصاف
حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے پیر یا بزرگ سے بیعت ہونا درست ہے جس میں حسبِ ذیل اوصاف پائے جائیں:
۱۔ پیر کتاب وسنت کا علم رکھتا ہو، خود پڑھ کرعلم حاصل کیا ہو یا کسی بزرگ کی صحبت حاصل کی ہو۔ بہرحال اس کے پاس کتاب وسنت کا علم ہونا چاہیے۔
۲۔ کبائر سے مجتنب ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرے۔ کبائر کا مرتکب بیعت کا اہل نہیں ہوتا کیونکہ وہ فساق میں شمار ہوتا ہے۔
۳۔ بیعت لینے والا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہو۔
۴۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکرکا عامل ہو۔ اپنے متعلقین کو اچھی بات کا حکم دے اور اگر ان میں کوئی بری بات دیکھے تو فوراً روک دے۔
۵۔ پیر خود رَو نہ ہو بلکہ یہ طریقہ اس نے بزرگوں سے سیکھا ہو یا ان کی صحبت اختیار کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹا جیسا کیسا بھی ہو، گدی نشین ہو گیا۔ نہ کسی سے سیکھا نہ کسی کی صحبت اختیار کی اور نہ علم حاصل کیا۔ یہ سلسلہ جو آج کل رائج ہے ،تباہ کن ہے ۔
اگر ان شرائط کو پورا کرنے والا کوئی بزرگ مل جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے تاکہ انسان شیطان کے پھندے سے محفوظ رہ سکے۔ ویسے یہ بیعت نہ فرض ہے اور نہ واجب البتہ سنت ہے۔ بزرگان دین میں سے حضرت دقاقؒ اور شیخ عبد القادر جیلانی ؒ سے منقول ہے کہ اگر کوئی کامل آدمی مل جائے تو بیعت کر لینی چاہیے البتہ کسی غلط کار، فاسق، شرکیہ اور بدعتی اعمال کرنے والے پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ مولانا رومیؒ فرماتے ہیں:
اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
پس بہر دستے نباید داد دست
اس قسم کے لوگ انسانی شکل میں شیطان ہیں اس لیے ہر ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ دینا چاہیے ورنہ وہ شرک اور بدعت میں مبتلا کر دیں گے اور انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔
افغانستان میں امریکی پالیسی کا ایک جائزہ
پروفیسر میاں انعام الرحمن
۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کو ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر ہونے والے حملے اپنی نوعیت کے لحاظ سے حیران کر دینے والے تھے۔ عالمی سطح پر رائج رجحانات کے پس منظر میں یہ واقعہ ’’اپ سیٹ‘‘ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے امریکہ کو فوجی، اقتصادی اور نفسیاتی حوالے سے شدید دھچکا لگا۔ نفسیاتی بازیابی تو شاید فوری ممکن نہیں ہوگی تاہم کچھ نہ کچھ مداوا کرنے کے لیے امریکہ نے کسی ثبوت اور تصدیق کے بغیر اس واقعہ کی ذمہ داری اسامہ بن لادن اور اس کے نیٹ ورک القاعدہ پر ڈال کر ان کے خلاف بین الاقوامی رائے عامہ کو ہموار کیا اور پھر عالمی تعاون حاصل کر کے افغانستان پر حملہ کر دیا۔
امریکی پالیسی وسیع تر تناظر میں
اگرچہ ’’دہشت گردی‘‘ کے خلاف امریکی مہم کئی قدم آگے بڑھ چکی ہے اور اب نظری سے زیادہ عملی نوعیت کے سوالات درپیش ہیں، لیکن یہ بنیادی سوال اب بھی غور وفکر کا محتاج ہے کہ کیا دہشت گردی کے مبینہ ملزموں کے خلاف امریکہ کے پاس ملٹری آپریشن کی صورت میں ایک ہی آپشن تھا؟
میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ۱۱ ستمبر کے بعد امریکی موقف بہت غیر ذمہ دارانہ رہا۔ ثبوت فراہم کیے بغیر اسامہ کو ان کے حوالے کرنے کا امریکی مطالبہ اخلاقی اور قانونی حوالے سے قابل مذمت تھا۔ کوئی بھی آزاد اور خود مختار ریاست ایسے کسی مطالبے کو تسلیم نہیں کر سکتی لہذا افغانوں کا فیصلہ حیران کن نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کا یہ بے جواز مطالبہ افغانستان میں مداخلت کے لیے محض ایک بہانہ تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی تباہی سے اس کا جو نقصان ہوا، سو ہوا لیکن اب وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راکھ کے اس ڈھیر سے مفادات کی نئی عمارت تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ امریکی پالیسی سازوں نے حقیقتاً وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔
اس سلسلے میں ایک فرضیے پر غور کیجیے تو امریکی عزائم کی نوعیت اور ان کی پالیسی کے تزویراتی مضمرات (Strategic implications)کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ افغانستان پر امریکی حملہ اصل ہدف سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہو؟ یعنی امریکہ کا اصل ہدف تو کہیں اور ہو اور دنیا اور عالم اسلام کی توجہ افغانستان پر مبذول کرا کے وہ اپنے اصل ہدف پر خفیہ کام کر رہا ہو؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں ہے تو پھر موجودہ جنگ محض ایک ریہرسل ہے جبکہ اصل اور باقاعدہ جنگ بعد میں ہوگی۔
اب یہ دیکھیے کہ اس ریہرسل سے امریکہ کون سے فوجی، سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی فوائد حاصل کر سکتا ہے؟
۱۔ اب تک کی صورتِ حال کے مطابق امریکی حکمت عملی مختلف مرحلوں (Phases)میں تقسیم ہے۔ پہلے مرحلے میں صرف ہوائی حملے ہوئے اور وہ بھی اس طرح کہ خوب شور مچایا گیا کہ ’’میں آ رہا ہوں‘‘۔ ہتھیاروں کی بابت بھی بتایا گیا کہ ان کی یہ قیمت اور اہلیت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانوں نے سب کچھ جانتے ہوئے اپنے تحفظ کے اقدامات نہیں کیے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اپنا مخصوص اسلحہ جو ان کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتا تھا، امریکی حملوں کے لیے وہیں پڑا رہنے دیا ہوگا؟ یقیناًافغان ایسی غلطی نہیں کرسکتے تھے اور نہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ افغان ایسی غلطی کریں، ورنہ پہلے شور مچانے کا کیا فائدہ؟
پہلے مرحلے میں امریکیوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ افغانی، حملے کی صورت میں اپنا اسلحہ کیسے، کتنی مدت میں اور کہاں شفٹ کرتے ہیں۔ امریکی انٹیلی جنس اس حوالے سے کام کر رہی ہوگی۔ پھر سب نے پڑھا اور سنا کہ امریکہ کے بقول فضائی حملے پچاسی فیصد کام یاب رہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ سفید جھوٹ تھا۔ اس پراپیگنڈے کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ افغانی کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ اس پچاسی فیصد کامیابی کے اثر کو کم بلکہ ختم کرنے کے لیے افغانوں کا طرز عمل کیا ہوتاہے؟ اس میں ’’سرپرائز‘‘ اور ’’منفیت‘‘ کس حد تک ہوگی؟
پہلے مرحلے کی یہ معلومات امریکہ کو ’’فائنل فیز‘‘ میں بہت کام دیں گی۔ جنگ کا فائنل فیز بہت جلد متوقع نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ چند سال بعد شروع ہو۔ کوریا جنگ میں چین نے تین مختلف مرحلوں میں مداخلت کر کے امریکہ کوحیران کر دیا تھا اور امریکی ملٹری کمانڈ ان مرحلوں کی پیش بینی نہیں کر سکی تھی۔ امریکی کوریا، ویت نام اور کیوبا میں اپنے سابقہ تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔
اس جنگ کا دوسرا مرحلہ زمینی حملوں کا ہے۔ اس کا مقصد بھی فائنل فیز کے لیے امریکی فوج کی تربیت اور امریکی جرنیلوں کو افغانستان سے متعلق ’’عملی سہولت‘‘ بہم پہنچانا ہے تاکہ وہ افغان خطرے کو گہرے انداز سے اسٹڈی کر سکیں اور اس علاقے کی مناسبت اور افغانوں کی نفسیات کے مطابق کوئی نیا طریقہ کار (Mode of action) آزما سکیں۔ نیز نئے ہتھیاروں کی افادیت کا بھی پتہ چل سکے تاکہ فائنل فیز میں امریکہ کو سبکی نہ اٹھانی پڑے۔
۲۔ فوجی مہم کے علاوہ سیاسی میدان میں بین الاقوامی برادری بالخصوص مسلم ممالک کے رویوں کوجانچا جارہا ہے کہ ان میں ڈپلومیسی کی کتنی اہلیت ہے اور وہ اپنے مفادات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مسلم ممالک کے عوام کو خاص کوریج دی جائے گی تاکہ فائنل فیز میں ان کی قوت کو امریکی مفادات میں چینلائز کیا جا سکے۔ مسلم ممالک کے انٹیلی جنس کے نیٹ ورک پر امریکیوں کی خاص نظر ہوگی۔ ان کی معلومات تک رسائی، تجزیہ اور بھانپ لینے کی قوت کو سٹڈی کیا جائے گا۔ امریکہ کے لیے یہ معلومات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ یہ ایجنسیاں سفارت کاری، حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ اور رائے عامہ کو ہموار کرنے میں کتنی موثر ہیں۔
۳۔ پچھلے چند سالوں میں مسلم دنیا کی جہادی تنظیمیں تیزی سے فعال ہوئی ہیں اور عوام میں ان کو پذیرائی ملی ہے۔ موجودہ امریکی حملے میں، ظاہر ہے کہ ان تنظیموں کی ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ ہیں اور تقریباً تمام بڑی تنظیمیں افغانستان کی مدد کرنا چاہتی ہیں اور غالباً کر رہی ہیں۔ اس طرح امریکہ نے تمام جہادی تنظیموں کو افغانستان پر فوکس (Focus)کر دیا ہے اور یہ تنظیمیں فرنٹ پر آگئی ہیں۔ موجودہ جنگ سے ان تنظیموں کی سطح، صلاحیت، ان کے باہمی روابط اور مسلم عوام میں ان کی مقبولیت کھل کر سامنے آئے گی اور ان تنظیموں سے متعلق ایسی معلومات فائنل فیز میں امریکہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ موجودہ جنگ کے دوران میں ہی امریکہ کو ان تنظیموں میں سے اپنے مطلب کے لیڈر بھی مل جائیں گے جو فائنل فیز کے آنے تک ان تنظیموں کی نئی نہج متعین کر کے امریکی مفادات کو تقویت بخش سکیں گے۔
۴۔ امریکہ اس جنگ سے اقتصادی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اپنے زنگ آلود اسلحے کو استعمال میں لانے کے ساتھ ساتھ نئے ہتھیاروں کی افادیت کا بھی پتہ چل سکے گا اور خرچ دوسرے ملکوں پر ڈال دیا جائے گا۔ ملک کے اندر عوام سے اپیل کی جائے گی کہ جنگ کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں لہذا حکومت کی مدد کی جائے۔ یہ جنگی فنڈ اقتصادی وفوجی مہم جوئی کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔
۵۔ افغانستان میں سابق سوویت یونین کی ناکامی کو امریکہ نے بہت باریک بینی سے اسٹڈی کیا ہے۔ اس ناکامی میں ظاہر ہے کہ امریکہ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اس جنگ میں چین نے بھی افغانوں کی مدد کی تھی۔ اسی طرح کچھ دوسرے ممالک بھی تھے اور امداد کی نوعیت میں بھی فرق تھا۔ امریکہ موجودہ جنگ میں کسی ایسے ہاتھ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا جو افغانستان میں امریکی ناکامی کا سبب بننے کی سکت رکھتا ہو۔ امریکہ کی کوشش ہوگی کہ موجودہ جنگ کے دوران میں اس ہاتھ کی نشان دہی ہو سکے تاکہ اس سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کی جا سکے اور فائنل فیز میں اس کا حشر سوویت یونین جیسا نہ ہو۔ اس عمل کے دوران میں امریکی انٹیلی جنس کی کارکردگی کو تنقیدی نظر سے دیکھا جائے گا اور امریکی فیصلہ سازی کے عمل میں موجود خامیوں کی نشان دہی کر کے ان کا سدباب کیا جائے گا۔
اگر امریکی صدر کی ٹیم پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو بیشتر سرد جنگ کے تجربہ کار چہرے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ افغان جنگ کو Anticipate کر رہا تھا۔ چونکہ افغان روسیوں کے خلاف جنگ لڑ چکے ہیں اس لیے ان کا طریقہ جنگ روسی اثرات کا حامل ہوگا۔ زیادہ تر اسلحہ بھی روسی نوعیت کا ہوگا اور ان کی امداد کرنے والے متوقع ممالک بھی سابق کمیونسٹ ہوں گے۔ لہذا کمیونسٹ نفسیات (Psyche) سے واقف لوگوں کی ٹیم ہی ایسی ’’پر پیچ‘‘ جنگ لڑ سکتی ہے جس کے کئی مرحلے ہیں ور فائنل فیز میں جیت سے ہی امریکہ اپنی بالادستی قائم رکھ سکتا ہے۔
اس ساری گفتگو سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ نے افغانستان کو ہی کیوں اپنے ٹارگٹ کے طور پر منتخب کیا؟ اس کی وجوہ یہ ہیں:
(i) تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تاریخ جغرافیے کو بدلتی رہتی ہے لیکن افغانستا ن کا جغرافیہ ایسا ہے جو خود تاریخ بنا سکتا ہے۔ افغانستان کا جغرافیہ امریکہ کے لیے ایک سیاسی خطرے (Political threat) کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ سائنسی وتکنیکی ترقی سے جغرافیے کی اہمیت میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن افغانوں نے اپنے مخصوص جغرافیے کی اہمیت کو برقرار رکھا ہے۔
(ii) افغانی جنگ آزمودہ لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا میں اتنے تربیت یافتہ جنگ جو شایدکہیں بھی موجود نہیں۔
(iii) باقی تمام مسلم ممالک امریکہ کے نشانے کی زد میں (Vulnerable) ہیں۔ صرف افغانستان ایک استثنائی مثال ہے، لہذا امریکی اس خطرے سے نمٹنا چاہتے ہیں۔
(iv) مسلم جہادی تنظیموں کی تربیت گاہ افغانستان کی پہاڑیاں ہیں۔ اگر عالم اسلام اور امریکہ کی تکنیکی صلاحیتوں کا تقابل کیا جائے تو توازن کا نشان تک نہیں ملتا۔ صرف ایک پاکستان ایٹمی قوت ہے لیکن وہ بھی سائنسی وتکنیکی اعتبار سے امریکہ سے بہت پیچھے ہے۔ نظر آ رہا تھا کہ مغرب اسلام کشمکش میں Nuclear Deterrent موثر ثابت نہیں ہوگا، البتہ جہادی تنظیمیں ایک موثر Deterrentکے طور پر ابھر رہی تھیں۔ امریکہ اس Deterrent کو ختم کر کے اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس تناظر میں امریکیوں نے اعلیٰ Threat perception کا ثبوت دیا ہے۔
۶۔ اس جنگ سے امریکہ کو حاصل ہونے والے تہذیبی فوائد کا اندازہ اس امیج سے کیا جا سکتا ہے جوکابل میں شمالی اتحاد کے داخلے کے بعد تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ سمیت انٹرنیشنل میڈیا جو خبریں اور تصاویر پیش کر رہا ہے، ان سے اس تصور کو تقویت ملتی ہے کہ:
۱۔ طالبان کے زیر حکومت عوام جبر کا شکار تھے، اب انہیں معاشرتی آزادیوں سے ہم کنار کیا گیا ہے۔
۲۔ شعائر اسلام فرسودگی کی علامت ہیں اور ان سے اجتناب جدیدیت ہے۔
گویا مغربی رویے کے بین السطور ان کی تہذیبی برتری جھلکنا شروع ہو گئی ہے۔ ’’تہذیبوں کے تصادم‘‘ سے خائف مغربی قوتیں جارحیت سے اپنا دفاع کرنا چاہتی ہیں۔ اگرچہ طالبان کی بے جا سختی اور بے لچک رویہ قابل تعریف نہیں ہے اور اسلام کی تعبیر وتشریح میں عصری تقاضے ان کے پیش نظر نہیں رہے، تاہم اگر ہم مذکورہ امور کو مد نظر رکھیں تو افغانستان پر حملے کی امریکی پالیسی کے پوشیدہ (Invisible) پہلو کی بعض نئی جہتیں آشکارا ہوں گی۔ امریکی پالیسی کے خدوخال جیسے جیسے بھرپور صورت اختیار کریں گے، مسلم عوام کے ذہنی تحفظات (Mental reservations) میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ناگزیر طور پر ہر مسلم ریاست میں معاشرتی سطح پر ’’دوئی‘‘ کو فروغ ملے گا۔ قدامت پسند ردِ عمل میں مزید قدامت پسند ہو جائیں گے اور ان کی قدامت پسندی کے مضمرات اور منفیت جدت پسندوں کو ان سے مزید دور کرنے کا باعث بنیں گے۔ اس طرح ہر ریاست میں دو معاشرتی گروہ آمنے سامنے ہوں گے۔ عالمی اسلامی معاشرہ بھی واضح دوئی کا حامل ہوگا۔ مغربی طاقتوں نے کمالِ تدبر سے متوقع مغرب اسلام کشمکش کو خود اسلامی معاشروں میں محدود کر دیا ہے جہاں جدت پسند ان کے نمائندے ہوں گے اور قدامت پسند مخالف۔ اس پر طرہ یہ کہ مغربی طاقتوں کے مخالف قدامت پسند بھی اسلام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا پیش کردہ اسلام اور اس کی تعبیر وتشریح رد عمل پر مبنی ہوگی لہذا اصل اسلام سے دور ہوگی۔ اس طرح اسلام کی حقیقی Orientation سامنے نہ آنے سے مغرب کی تہذیبی برتری کے لیے تمام راستے ہموار ہوتے جائیں گے۔
موجودہ صورتِ حال میں چین کی پالیسی بھی معنی خیز ہے۔ اسلامی تہذیب کی خلقی استعداد سے چین بھی خوف زدہ تھا۔ افغانستان میں امن کا قیام اور اس کے ساتھ اسلامائزیشن کے اقدامات چین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ اگرچہ طالبان کا اسلام خاصا یک رخا تھا لیکن بہتری کے امکانات، بہرحال، موجود تھے۔ پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیائی مسلم ریاستوں میں اسلام کی تعبیر وتشریح اور نفاذ کے حوالے سے دانش ورانہ مکالمہ شروع ہو سکتا تھا۔ یہ مکالمہ ان ریاستوں کو کوئی معاشرتی نقطہ اتصال بھی فراہم کر سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چین کی پالیسی اسی تناظر میں تشکیل دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ چین میں اسلامی دعوتی سرگرمیاں قبل از وقت تھیں یا کم از کم ان کا پھیلاؤ اور طریقہ کار ایسا تھا کہ چین تحفظات کا شکار ہو گیا۔ ماضی میں چین کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں۔ عام قیاس آرائیاں یہی تھیں کہ مغرب اور اسلام کی تہذیبی کشمکش میں چین کا وزن اسلام کے پلڑے میں پڑے گا لیکن تازہ ترین صورت حال سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مغربی طاقتوں نے چین کو کم از کم خاموش رہنے پر رضامند کر لیا ہے۔
اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جاری موجودہ جنگ صرف ایک ریہرسل ہے جس سے متنوع وقتی اور مستقل فوائد کے ساتھ ساتھ ایسی معلومات کا حصول مقصود ہے جو جنگ کے فائنل فیز کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ امکان ہے کہ روس اور چین جہادی تنظیموں کے خاتمے کی حد تک امریکہ کا ساتھ دیں گے لیکن جہاں تک افغانستان کے جغرافیے کا سوال ہے، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ اسے فتح کرے لہذا اس جنگ کے دوران میں دوستیاں دشمنیاں بھی بدلتی رہیں گی۔
موجودہ صورت حال ۔ چند امکانات
مذکورہ بالا بحث کا تعلق امریکی پالیسی کے وسیع تر تناظر سے تھا۔ جہاں تک موجودہ جنگ کے ظاہری (Visible) پہلو کا تعلق ہے تو اس کو Discussکرنا اور جانچنا بظاہر جتنا آسان نظر تا ہے، اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے۔ طالبان کی پسپائی کے بعد صورت حال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں قطعیت سے کچھ کہنا فی الحال خاصا مشکل ہے۔ پاکستان اور عالم اسلام میں حکومتی رویے سے قطع نظر عوامی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ طالبان کی پسپائی ایسا دھچکا نہیں جس کے لیے لوگ ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ ایسا ہونا ممکنات میں سے تھا۔
اس حوالے سے آئندہ امریکی حکمت عملی کچھ اس قسم کی ہو سکتی ہے:
۱۔ کابل سلگتا رہے تاکہ افغان داخلی معاملات میں الجھے رہیں اور بقول امریکہ خارجی دنیا کے لیے دہشت گردی کا باعث نہ بنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکو (Echo)ممالک کی باہمی تجارت فروغ نہ پا سکے۔ یہ چیز چین اور بھارت کے مفاد میں بھی ہے۔ ایکو کی مضبوطی سے بھارت اور چین اقتصادی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بھارت ،چین اور ایکو کی اقتصادی مسابقت مزید پیچیدگیوں کو جنم دے سکتی ہے۔ اس طرح افغانستان میں پائیدار امن اور مضبوط مرکزی حکومت کا قیام بعض ریاستوں کے مفادات سے متصادم ہے۔
۲۔ افغانستان کے کم از کم دو حصے کر دیے جائیں، شمالی افغانستان اور جنوبی افغانستان۔ ان میں اگر کوئی تعلق قائم بھی رکھا جائے تو وہ برائے نام اور معمولی نوعیت کا ہو۔ البتہ اس قسم کے پلان کی پاکستان شدید مخالفت کرے گا کیونکہ اس کے سرحدی صوبہ کو جنوبی افغانستان میں ضم کرنے کی داخلی کوششیں شروع ہو سکتی ہیں اور ایسے عناصر موجود ہیں جو مہروں کا کام دے سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی سلامتی اور وحدت پارہ پارہ ہو جائے گی۔ پاکستان کی ٹوٹ پھوٹ کے اثرات سے بھارت بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے امکان یہی ہے کہ بھارت افغانستان کی تقسیم کے کسی پلان کو تحفظات کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔
۳۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حالت (Stuatus quo) کو برقرار رکھا جائے تاکہ وار لارڈز کو بوقتِ ضرورت ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اگر یہ صورت اپنائی جاتی ہے تو امریکہ کو مستقل طور پر عملاً ملوث رہنا پڑے گا جو ایک تھکا دینے والا اور اعصاب شکن عمل ہوگا۔
۴۔ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کی زیرنگرانی امن فوج متعین کر دی جائے۔ اگر امریکی اور یورپی طاقتوں کی فوج بھیجی جاتی ہے تو امریکہ کو سٹرٹیجک فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلم ممالک کی افواج کو وہاں تعینات کیا گیا تو غلط فہمیوں کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ ترکی، ایران اور پاکستان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ طالبان کی حکومت اور افغانستان پر ان کے کنٹرول سے پاکستان مستقبل کے حوالے سے بہت پرامید جبکہ ایران اور ترکی تحفظات کے شکار تھے۔ موجودہ صورت حال سے ایران اور ترکی کو ایک Edge ملا ہے جس سے دونوں ممالک فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ترکی کی فوج ویسے بھی پروفیشنل نہیں۔ اس کے سیاسی مزاج اور دل چسپیوں (Political Orientaion)سے کون واقف نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایکو کا پلیٹ فارم ان ممالک کو کوئی بہتر راہ دکھا سکے۔
یہ امکانات امریکی نقطہ نظر سے تھے۔ اگر طالبان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں:
۱۔ ان کی پسپائی حکمت عملی کے ماتحت ہے۔ اب وہ اپنی کچھار یعنی اصل علاقے میں واپس آ گئے ہیں۔
۲۔ شمالی اتحاد کو کابل پر قابض ہونے کا موقع دیا گیا تاکہ ان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو، کیونکہ طالبان کو امریکی افواج اور امریکی ٹیکنالوجی سے زیادہ خطرہ شمالی اتحاد سے ہے۔
۳۔ پسپائی اختیار کر کے طالبان امریکی ترکش کے تیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے امریکی عزائم کی نوعیت اور طریقہ کار ان پر مزید واضح ہوگا۔
۴۔ امریکی حملے کے پہلے مرحلے کے دوران میں طالبان کا استقلال شاید یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ وہ حکومت پاکستان کے زیر اثر نہیں بلکہ خود مختار ہیں۔ طالبان نے جس قسم کی مدافعت کی ہے، اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے۔ اگر وہ بہت جلد پسپائی اختیار کر لیتے تو ان کے متعلق یہی تاثر پھیلتا کہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر وہ زیرو ہیں۔ اپنا کم سے کم نقصان کرواتے ہوئے انہوں نے ایک مہینے سے زیادہ مدافعت کی ہے جس سے یہ تاثر پھیلا ہے کہ ان میں لڑنے کی قوت موجود ہے۔ اب اگر پسپائی کے بعد وہ فوراً گوریلا کارروائیاں شروع کرتے ہیں اور کوئی خفیہ ہاتھ ان کی مدد پر آمادہ ہو جاتا ہے تو طالبان کی کارروائیوں کے تسلسل کو ان کی سابقہ مدافعتی سرگرمیوں کے متوازی سمجھا جائے گا کہ ان میں ابھی قوت باقی ہے۔ یہ باقی قوت خاصی طویل مدت پر محیط ہو کر دشمن کو ناکوں چنے بھی چبوا سکتی ہے۔
بہرحال صورتِ حال چاہے امریکی عزائم کے مطابق ہو یا ان کے برعکس، پاکستان کو اپنی پالیسی اس نوعیت کی رکھنا ہوگی کہ حالات کا تغیر اس کے لیے مشکلات کا باعث نہ بن سکے۔ جہاں تک پاکستان کے مفادات کا تعلق ہے تو اسے بھی طالبان کی طرح عارضی پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ وقتی اور عارضی نقصان سے قطع نظر ہمیں اپنے مستقل اور پائیدار مفاد پر نظر رکھنا ہوگی۔ عالمی طاقتیں طویل عرصے تک افغانستان میں اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر سکیں گی۔ پاکستان کو اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتے ہوئے اپنے کارڈز استعمال کرنا ہوں گے۔ افغانستان کی اہمیت پاکستان کے لیے ہمیشہ قائم رہے گی اور افغانستان کا مستقبل ہمیشہ پاکستان سے وابستہ رہے گا۔
چین میں مسلمان علیحدگی پسندوں کو سزائے موت
اولیور آگسٹ
مسلمان دہشت گردوں کا واسطہ کل سزائے موت دینے والے عملے (Death squad)سے تھا۔ شراب کے اثر سے ان کے حواس بجا نہیں تھے اور قہقہے لگاتے ہجوم کے درمیان میں سے انہیں ایک کھلی گاڑی پر سزائے موت کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ چین کے شمال مغربی علاقے کاشغر میں سہ پہر کی روشن دھوپ میں کئی درجن مسلمان قیدی نیلی گاڑیوں پر قطار میں کھڑے تھے۔ ان کے حواس بجا نہیں تھے اور وہ اپنے ارد گرد سے تقریباً بے خبر تھے۔ ماؤزے تنگ کے ۱۰۰ فٹ اونچے مضبوط مجسمے کے نیچے کھڑے یہ قیدی، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، آہستہ آہستہ لڑکھڑا رہے تھے اور سفید دستانوں والے سپاہی انہیں سہارا دے رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں اور ان کی گھورتی ہوئی لیکن خالی نظریں ان کی پریشان فکری پر دلالت کر رہی تھیں۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کا سامنا جلاد سے ہونے والا ہے۔ ان کے عقیدے کی انتہائی تذلیل کرتے ہوئے انہیں ان کے آخری کھانے کے ساتھ شراب پلائی گئی تھی۔بظاہر ان لوگوں کو ترکی اکثریت کے صوبے سنکیانگ میں ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کے لیے لڑتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ علیحدگی پسند کئی سالوں سے مسلم اکثریت کے اس علاقے کو چین کے قبضے سے چھڑا کر یہاں ’’مشرقی ترکستان‘‘ کے نام سے ایک نیا ملک قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان اور مغرب کے مابین حالیہ تصادم نے اسلامی جوش وجذبے کو اور ہوا دی ہے۔ بہت سے مقامی لوگ طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک بیجنگ اور واشنگٹن کے ’’کافروں‘‘ میں کوئی فرق نہیں۔
افغانستان کی صورت حال کے ممکنہ اثرات کے خدشے کے پیش نظر بیجنگ کی وفادار ایلیٹ فوج گزشتہ ہفتے سے یہاں تعینات ہے۔ اس بحران نے چینی حکمرانوں کو مزید سختی کے ساتھ علیحدگی پسندوں کو کچلنے کا موقع فراہم کیا ہے اور گزشتہ روز بیجنگ حکومت کے سرکاری عہدیداروں نے سزائے موت سے کچھ پہلے کے ان غم ناک لمحات کو ایک سیاسی اجتماع میں تبدیل کر دیا۔مسلمان قیدیوں کی گاڑیوں کی قطار کے سامنے کمیونسٹ پارٹی کے سینکڑوں ارکان ترتیب سے بنی ہوئی قطاروں میں بیٹھے تھے اور صدر ژیانگ زیمن (Jiang Zemin)کے (آہنی عزم کا) حوالہ دیتی ہوئی خون جما دینے والی تقریروں کی داد دے رہے تھے۔ بینروں، جھنڈوں اور پراپیگنڈا کا مقصد پورا کرتی ہوئی تصویروں میں گھرے ہوئے مسلمان قیدی خاموشی کے ساتھ (اپنے ذہنوں پر چھائی ہوئی) شراب کی دھند کے پار دیکھنے کی کوشش رہے تھے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر جس نے شہر کے مین روڈ کو بلاک کررکھا تھا، ایک گھنٹے تک جاری رہا۔ پھر ایک پولیس کا سائرن بجنے کے بعد گاڑیوں کے قافلے نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ لبریشن سٹریٹ کے دونوں طرف موجود ہزاروں تماشائی گزرتی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سزائے موت کے میدان کو جاتے ہوئے قیدیوں کوآمنے سامنے دیکھ کر کئی لوگ بے چین لیکن بظاہر ہنس رہے تھے۔ صرف چند بچے، جنہوں نے اپنی باپردہ ماؤں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ہجوم سے پیچھے ہٹ گئے۔ قیدی کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ سب کی گردن میں ایک بڑا سا اشتہار لٹکا ہوا تھا جو چینی زبان کے بجائے مقامی ترکی زبان میں لکھا گیا تھا۔ ان پر ان قیدیوں کے جرائم لکھے ہوئے تھے جن میں عوامی امن وامان کو خراب کرنا اور دوسرے عام قسم کے جرائم شامل ہیں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ ان میں سے دو قیدیوں کو تو ابھی سزائے موت دے دی جائے گی جبکہ باقی واپس جیل میں چلے جائیں گے۔
پیپلز سکوائر کے نزدیک جہاں سڑک تقسیم ہو جاتی ہے، قافلہ بھی تقسیم ہو گیا اور زیادہ تر گاڑیاں مقامی پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئیں جو شہرکی خستہ حال دیوار کے ساتھ واقع ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی میں دوسری طرف جانے والے قافلے کا تعاقب کیا جو پولیس کی کچھ کاروں اور صرف ایک گاڑی پر مشتمل رہ گیا تھا جس پر دونوں بد نصیب قیدی سوار تھے۔ ہجوم اب بھی میلوں تک سڑک کے دونوں جانب کھڑا تھا۔ غالباً بہت سے تماشائیوں کو ان کے افسروں کی طرف سے حکم تھا کہ وہ اس خاص موقع پر موجود رہیں جس کا انتظام پارٹی عہدیداروں نے سوچے سمجھے پروگرام کے تحت لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ صحرا میں واقع اس سرسبز اور قدیم شہر میں سلک روڈ پر ہم کئی مسجدوں کے سامنے سے گزرے۔ پٹرول اسٹیشن پر موجود ایک شخص نے بتایا کہ قیدیوں سے بھری ہوئی ایسی گاڑیاں وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ ہموار سڑک جس کے دونوں جانب درخت اور مٹی کے جھونپڑے بنے ہوئے تھے، صحرا کے کنارے تک جا رہی تھی۔ شہر کے اختتام پر گاڑی اچانک ایک ملٹری ٹریننگ گراؤنڈ میں داخل ہو گئی۔دونوں بد قسمت قیدی صحرائے کاشغر کے پار چین اور افغانستان کے درمیان حائل پہاڑی سلسلے پر آخری نظر ڈال سکتے تھے۔ جب انہیں گاڑی سے اتارا گیا تب بھی ان کے ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے ۔ میں نے سزائے موت کا منظر نہیں دیکھا البتہ اس کے فوراً بعد پہنچ کر میں نے ایک عینی شاہد سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ ان کی گردن کے پچھلی حصے میں گولی ماری گئی اور سارا کام صرف تین منٹ میں مکمل ہو گیا۔ مقامی رواج کے مطابق یہ گولی مجرم کے خاندان کو بھیج دی جائے گی تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے وارننگ بن سکے۔
(ڈیلی ’’دی ٹائمز‘‘، ۲۶ ستمبر ۲۰۰۱)
(ترجمہ: ادارہ)
سیدنا عمرؓ اور قتلِ منافق کا واقعہ
محمد عمار خان ناصر
ہمارے معاشرے میں پیشہ ور اور غیر محتاط واعظین نے جن بے اصل کہانیوں کو مسلسل بیان کر کر کے زبان زدِ عام کر دیا ہے، ان میں سے ایک سیدنا عمرؓ کے ایک منافق کو قتل کرنے کا واقعہ بھی ہے۔ زیر نظر سطور میں محدثانہ نقطہ نظر سے اس واقعہ کی پوزیشن کو واضح کیا جا رہا ہے۔
اس واقعے کی تفصیل میں حافظ ابن کثیرؒ نے سورۃ النساء کی آیت ۶۵ کے تحت دو روایتیں نقل کی ہیں:
پہلی روایت ابن مردویہؒ اور ابن ابی حاتم ؒ کے حوالے سے ہے جس کی سند حسب ذیل ہے: یونس بن عبد الاعلی اخبرنا ابن وھب اخبرنا عبد اللہ بن لہیعۃ عن ابی الاسود
دوسری روایت حافظ ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحمن کی تفسیر کے حوالے سے نقل کی گئی ہے جس کی سند یہ ہے : حدثنا شعیب بن شعیب حدثنا ابو المغیرۃ حدثنا عتبۃ بن ضمرۃ حدثنی ابی
حکیم ترمذی نے ’نوادر الاصول‘ میں یہی واقعہ کسی سند کے بغیر مکحولؒ سے نقل کیا ہے اور ’نوادر‘ کے حوالے سے حافظ سیوطیؒ نے بھی اس واقعے کو ’الدر المنثور‘ میں درج کیا ہے۔ (۱)
حافظ ابو اسحاقؒ کی تفسیر میں منقول روایت کے الفاظ یہ ہیں:
’’دو آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس جھگڑا لے کر آئے‘ آپ نے حق دار کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مقدمہ ہارنے والا کہنے لگا کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ دوسرے فریق نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا‘ ابو بکرؓ صدیق کے پاس چلو۔ دونوں ان کے پاس گئے اور مقدمہ جیتنے والے نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس جھگڑا لے کر گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ بھی یہی ہے۔ لیکن دوسرا فریق اس پر بھی راضی نہ ہوا اور کہنے لگا کہ اب ہم حضرت عمرؓ کے پاس جاتے ہیں۔ (ان کی خدمت میں حاضر ہو کر) مقدمہ جیتنے والے نے ان سے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس جھگڑا لے کر گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے‘ لیکن یہ ماننے سے انکار کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس شخص سے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر اندر گئے‘ تلوار ہاتھ میں لے کر باہر آئے اور اس شخص کی گردن اڑا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما‘‘ (آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم مان لیں اور پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں، اس سے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح سے تسلیم کر لیں)(۲)
ابن مردویہؒ سے منقول روایت کے آخر میں اس پر حسبِ ذیل اضافہ ہے:
’’دوسرا شخص بھاگا ہوا رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ‘ عمر نے تو میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور اگر میں بھاگ نہ آتا تو مجھے بھی قتل کر دیتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمر سے مجھے یہ توقع نہ تھی کہ وہ ایک مومن کو قتل کر ڈالے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصل تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ چنانچہ آپ نے اس آدمی کے خون کو رائیگاں قرار دیا اور عمرؓ سے قصاص نہ لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں دوسرے لوگ بھی اس طریقے پر عمل نہ کرنے لگیں‘ اگلی آیت میں فرمایاکہ اگر ہم ان پرلازم کر دیں کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے چند ہی لوگ اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ ‘‘ (۳)
نوادر الاصول میں مکحولؒ کی روایت کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہا :
’’یا رسول اللہ! عمرؓ نے اس آدمی کو قتل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کی زبان پر حق اور باطل کے مابین فرق کو واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ عمرؓ کو فاروق کا لقب دیا گیا۔‘‘ (۴)
یہ واقعہ روایت واسناد کے لحاظ سے نہایت کمزور اور ناقابل استدلال جبکہ درایت کے لحاظ سے بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔
پہلے سند کو لیجیے:
۱۔ نوادر الاصول کی روایت تو، جیسا کہ عرض کیا گیا، کسی سند کے بغیر صرف مکحولؒ سے منقول ہے جو تابعی ہیں اور کسی صحابی کے واسطے کے بغیر روایت نقل کر رہے ہیں۔ان کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ اکثر تدلیس کرتے ہوئے صحابہؓ سے روایات نقل کر دیتے ہیں حالانکہ وہ روایات خود ان سے نہیں سنی ہوتیں۔ (۵)
۲۔ ابن مردویہؒ اور ابن ابی حاتمؒ کی نقل کردہ روایت بھی منقطع ہے کیونکہ اس کے آخری راوی ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن نوفل ہیں جو تابعی ہیں۔ محدث ابن البوقی فرماتے ہیں کہ اگرچہ زمانی لحاظ سے امکان موجود ہے لیکن عملاً کسی صحابی سے ان کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں۔ (۶)
علاوہ ازیں ا س سند میں عبد اللہ بن لہیعۃجیسا بدنام ضعیف راوی موجود ہے۔ اس کے بارے میں علماء حدیث کے اقوال درج ذیل ہیں:
’’امام نسائی فرماتے ہیں‘ ثقہ نہیں ہے۔ ابن معین کہتے ہیں‘ کمزور ہے اور اس کی حدیثیں ناقابل اعتبار ہیں۔ خطیب کہتے ہیں‘ اس کے متساہل ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں منکر روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ابن مہدی‘ یحییٰ بن سعید اور وکیع نے اس کی روایت لینے سے انکار کیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں‘ بے کار احادیث بیان کرتا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں‘ میں نے اس کی روایات کو جانچ پرکھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تدلیس کرتے ہوئے درمیان کے کمزور راویوں کو حذف کر کے براہ راست ثقہ راویوں سے روایت نقل کر دیتا ہے۔‘‘ (۷)
۳۔ حافظ ابو اسحاق کی نقل کردہ روایت بھی منقطع ہے کیونکہ آخری راوی ضمر ۃ بن حبیب تابعی ہیں اور صحابی کا واسطہ موجود نہیں ۔ نیز سند کے ایک راوی ابو المغیرہ عبد القدوس بن الحجاج الخولانی کے بارے میں ابن حبانؒ کی رائے یہ ہے کہ وہ حدیثیں گھڑ کر ثقہ راویوں کے ذمے لگا دیتا ہے۔ (۸)
ازروئے درایت ان روایتوں پر حسب ذیل اعتراض وارد ہوتے ہیں:
ایک یہ کہ اگر مذکورہ واقعہ درست ہوتا تو سیدنا عمرؓ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا ایک سنہری موقع مدینہ منورہ کے منافقین کے ہاتھ آ جاتا اور وہ بھرپور طریقے سے اس کی اشاعت او ر تشہیر کرتے۔ چنانچہ ایسے واقعے کو‘ منطقی طور پر‘ کتب تاریخ وسیرت میں نمایاں طور پر مذکور ہونا چاہئے۔ جبکہ یہاں صورت حال یہ ہے کہ تاریخ اور تفسیر کی معرو ف اور قدیم کتابوں میں اس کا کہیں ذکر تک نہیں ۔ امام ابن جریر طبریؒ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر آیت کے شان نزول سے متعلق تمام اقوال وروایات کا احاطہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس واقعہ کی طرف ادنیٰ اشارہ تک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیرؒ نے اس کو غریب جدا کہا ہے ۔ اصول حدیث کی رو سے ایسے معروف واقعات کی روایت میں خبر واحد معتبر نہیں ہوتی۔
دوسرے یہ کہ اس میں سیدنا عمرؒ جیسی محتاط‘ سمجھ دار اور حدود اللہ کی پابند شخصیت کو ایک مغلوب الغضب (Rash) انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ سیدنا عمرؓ دین کے معاملے میں نہایت باحمیت اور غیرت مند تھے‘ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے ایسے کسی موقعے پر حد سے تجاوز نہیں کیا بلکہ کسی بھی اقدام کے لیے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی۔ چنانچہ یہ روایت واضح طور پر ان دین دشمن عناصر کی وضع کردہ معلوم ہوتی ہے جن کا مقصد اکابر صحابہ کرامؓ کی شخصیات کو مسخ کرنا اور انہیں داغ دار شکل میں پیش کرنا ہے۔
تیسرے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف عدل وانصاف کے تقاضوں کے برخلاف جانب داری کی نسبت لازم آتی ہے۔ اگر سیدنا عمرؓ نے اس شخص کو قتل کیا تو یہ واقعتا ایک خلاف شرع اقدام تھا کیونکہ اس شخص نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا جس پر وہ قتل کا مستحق ہوتا۔ اس کا لازمی نتیجہ قصاص تھا لیکن روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ جرم واقعتا سزائے موت کا مستحق تھا تو پھر اس کو ایک واضح ضابطے کی شکل میں بیان کر کے آئندہ کے لیے بھی اجازت (Sanction) دے دینی چاہیے تھی۔ اور اگر یہ قتل درست نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ کسی ایک شخص کی رعایت کرتے ہوئے، چاہے وہ کتنا ہی عظیم المرتبت ہو، عدل وانصاف کے تقاضوں کو معطل کر دے۔
حوالہ جات
(۱) نوادر الاصول، ۱/۲۳۲۔ الدر المنثور، ۲/۱۸۱
(۲) تفسیر القرآن العظیم‘ ۱/ ۵۲۱
(۳) نفس المصدر،
(۴) نوادر الاصول، ۱/۲۳۲
(۵) تہذیب التہذیب، ۱۰/۲۹۲
(۶) نفس المصدر، ۹/ ۳۰۸
(۷) نفس المصدر، ۵/ ۳۷۸‘ ۳۷۹
(۸) الکشف الحثیث، ۱/۱۷۱
لندن میں ’’قرآنی موضوعات‘‘ کی تعارفی تقریب
مولانا محمد عیسی منصوری
(برطانیہ کے معروف مسلم دانش ور اور ماہر اقبالیات پروفیسر محمد شریف بقا صاحب نے قرآن کریم کی آیات کو موضوعات اور عنوانات کے حوالے سے ایک ہزار کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب ’’قرآنی موضوعات‘‘ میں ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے جو ایک اچھی پیش کش ہے اور علم وعرفان پبلشرز، ۷۔سی ماتھر سٹریٹ، ۹۔ لوئر مال لاہور نے اسے شائع کیا ہے۔ ۱۲ اکتوبر ۲۰۰۱ء کو رابطہ عالم اسلامی لندن کے دفتر میں اس کتاب کی تعارفی تقریب سے ورلڈ اسلامک فورم کے چیئرمین مولانا محمد عیسیٰ منصوری نے مندرجہ ذیل خطاب کیا۔ ادارہ)
صدر محترم ومعزز سامعین!
لندن کے ادبی وعلمی حلقوں میں پروفیسر محمد شریف بقا صاحب کی ہستی پاکستان کی تاریخی تہذیب، علم وآگہی، تصوف وکلام اور فلسفیانہ انداز لیے ہوئے ایک منفرد وممتاز مقام کی حامل ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی فکر اور کلام سے بقا صاحب کی ارادت وعقیدت عشق کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کے کلام اور فکر کو اپنی تحقیق اور غور وخوض کا مرکز ومحور بنایا ہے ۔ یورپ اور امریکہ کی حد تک یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہاں کے علمی وادبی حلقوں میں آپ کا فکر وفن اور علمی، ادبی اور تحقیقی مقام مسلم ہے۔ آپ کی ہستی ادب وشاعری، فکری وتحقیقی اور علمی ودینی تمام حلقوں میں معروف ومحترم مانی جاتی ہے۔ آپ اپنے جذبِ دروں کے ساتھ طویل عرصہ سے برطانیہ میں فکر وتحقیق اور علامہ اقبال کے کلام کی تفہیم وتشریح میں سنجیدگی ویکسوئی سے منہمک ہیں۔ مغرب خصوصاً برطانیہ میں نئی نسل کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام اور فکر کی تفہیم وتشریح کا قابل قدر کام آپ کے قلم سے وجود میں آیا۔ آپ اپنے مرشد علامہ اقبال کی طرح فروعی نزاعات سے اجتناب برتتے ہوئے اسلام کی اساسی تعلیمات کو اشاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ کی دو درجن کے قریب تصانیف علم دوست حلقوں سے دادِ تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ بندہ تقریباً تین دہائیوں سے روزنامہ جنگ میں بقا صاحب کے بصیرت افروز اور فکر انگیز مقالات ومضامین کا قاری ہے اور تقریباًدو دہائیوں سے آپ سے تعارف وشناسائی حاصل ہے۔ آپ کی بیشتر تصانیف نظر سے گزری ہیں۔ آپ کی بے نظیر تصنیف ’’اقبال اور تصوف‘‘ پر مجھے تبصرہ اور اظہار خیال کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ جب بقا صاحب کے متعلق غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کا خلوص وبے لوثی، سادگی ووقار، درد مندی وسنجیدگی بقا صاحب کی شخصیت میں رچ بس گئے ہیں۔
اسلام کی ۱۴ سو سالہ تاریخ میں عربی کے بعد فارسی صدیوں سے اسلامی فکر وفلسفہ، علوم وآگہی، ادب وشاعری کے اظہار کا ذریعہ رہی ہے اور برصغیر میں تقریباً گزشتہ ہزار سالہ علمی وفکری خزانوں کی امین ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا بھی بڑا حصہ جو آپ کے فکر وفلسفہ کا نقطہ عروج ہے، فارسی ہی میں ہے۔ پروفیسر محمد شریف بقا صاحب کا فارسی مطالعہ خصوصاً فارسی زبان کے مفکرین، فلاسفہ، ادبا اور شعرا کا مطالعہ نہایت عمیق ووسیع ہے۔ اب تو طبقہ علما میں بھی فارسی میں گہری بصیرت رکھنے والے نایاب ہو چکے ہیں۔ اس جہت سے برطانیہ ویورپ میں شاید ہی بقا صاحب کی نظیر ملے۔ بقا صاحب اردو وفارسی دونوں زبانوں کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ حمد ونعت میں بھی ان کا جداگانہ رنگ ہے۔
اقبال کے متعلق مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندویؒ نے شہادت دی ہے کہ اس سو سال میں جدید طبقہ نے اقبال سے بڑا دیدہ ور پیدا نہیں کیا۔ وہ عصر حاضر کے مشرق کے سب سے بڑے مفکر وفلسفی ہیں۔ رشید احمد صدیقی مرحوم نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اقبال کا کلام اس صدی کا علم کلام ہے۔ اقبال کے فکر وکلام کی خصوصیات میں عشق رسول، قرآن سے شغف اور حضرات صوفیاء کرام کا سوز وساز شامل ہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اقبال پر دنیا کے بڑے مذہب کی گرفت اتنی نہیں جتنی ایک بڑی شخصیت کی ہے۔ وہ با خدا دیوانہ باش وبا محمد ہوشیار کا مصداق ہے اور اس کی شاعری وکلام کا خلاصہ ہے: ’’قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں‘‘ اور صوفیاء کا جذب دروں، سوز ومعنی اس کے شعر شعر سے ٹپکتا ہے۔ یہی خصوصیات برطانیہ ومغرب میں اقبال کے سب سے بڑے شارح وترجمان پروفیسر محمد شریف بقا صاحب کی ہیں۔ آپ کی دو درجن کے قریب تصانیف میں سب سے نمایاں اور بے مثال انہی تین موضوعات پر ہیں۔ سب سے طویل ’’قرآنی موضوعات‘‘ جو تقریباً ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے، دوسری ’’رسول اکرم ﷺ مغربی اہل دانش کی نظر میں‘‘ اور تیسری ’’اقبال اور تصوف‘‘۔
مولانا ندویؒ لکھتے ہیں: ’’اقبال کی زندگی پر یہ عظیم کتاب قرآن مجید اس قدر اثر انداز ہوئی ہے کہ اتنا وہ کسی شخصیت سے متاثر ہوئے نہ کسی کتاب سے لیکن اقبال کا قرآن پڑھنا عام لوگوں کے قرآن پڑھنے سے بالکل مختلف رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے (جو ایک باصفا درویش تھے) اقبال کو بچپن میں جب وہ صبح روزانہ قرآن پڑھنے بیٹھے، تلقین کی تھی کہ قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے قرآن اس وقت تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے قرآن کو اس طرح پڑھنا شروع کیا گویا وہ واقعی اس وقت نازل ہو رہا ہے۔ ایک شعر میں وہ اس کا اظہار یوں فرماتے ہیں:
ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف
اقبال نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید میں غور وفکر اور تدبر وتفکر کرنے میں گزاری۔ وہ ان کی محبوب ترین کتاب تھی جس سے انہیں نئے نئے علوم کا انکشاف ہوتا۔ اس سے انہیں ایک نیا یقین، نئی قوت وتوانائی حاصل ہوتی۔ جوں جوں ان کا مطالعہ قرآن بڑھتا گیا، ان کی فکر میں بلندی پیدا ہوتی گئی۔ موجودہ دور کی ظلمتوں میں اس نے قرآن کے بعد مولانا روم کو اپنا رہنما ومرشد بنایا۔ جس طرح مولانا روم کے دور میں فلسفہ یونان عقلوں پر چھا گیا تھا، حتیٰ کہ علما بھی اس سے ہٹ کر سوچ نہیں سکتے ہیں۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے ذریعے سے ایمان وایقان، عشق وسرور، سوز وساز کا پیغام دیا۔ اسی طرح اقبال کو بھی مغرب کے مادی وعقلی اور بے روح وبے خدا افکار ونظریات سے سابقہ پڑا۔ مادہ وروح کی کشمکش پورے عروج کے ساتھ سامنے آئی۔ اس قلبی اضطراب وذہنی انتشار کے موقع پر اقبال کومولانا روم نے بہت کچھ سہارا دیا۔ انہوں نے مولانا روم کو اپنا کامل رہنما تسلیم کیا اور صاف اعلان کیا کہ عقل وخرد کی ساری گتھیاں جسے یورپ کی مادیت نے الجھا رکھا ہے، اس کا حل صرف آتش رومی کے سوز ساز میں پنہاں ہے:
علاج آتش رومی کے سوز میں ہے ترا
اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جیحوں
اقبال کو عصر حاضر کے علما ودانش وروں، مفکرین وفلاسفہ سے سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر فلسفہ یونان اور روح کو چھوڑ کر الفاظ کی پرستش شروع کر دی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان براہ راست کتاب اللہ کا مطالعہ کریں اور اس کے علوم وحکمت سے مستفید ہوں۔
قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار، اخلاق وتہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہمہ گیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے جس کی کوئی نظر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل کی اور مستقل تہذیب کی تعمیر کی۔ ۱۴۰۰ برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے اور روز بروز اس کے یہ اثرات پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ پورے نظام زندگی کانقشہ پیش کرتی ہے جس میں عقائد، اخلاق، تزکیہ نفس، عبادات، معاشرت، تہذیب، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، قانون غرض حیات انسانی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مربوط ضابطہ بیان کرتی ہے۔ یہی نہیں، قرآن جو تصور کائنات وانسان پیش کرتا ہے، وہ تمام مظاہر اور واقعات کی مکمل توجیہ کرتا ہے۔ وہ ہر شعبہ علم میں تحقیق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جن حقائق کو علم کی حیثیت سے وہ پیش کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی آج تک غلط ثابت نہیں کیا جا سکا۔ فلسفہ وسائنس اور علوم عمران کے تمام آخری مسائل کے جوابات اس کے کلام میں موجود ہیں اور سب کے درمیان ایسا منطقی ربط ہے کہ ان پر ایک مکمل، مربوط اور جامع نظام فکر قائم ہوتا ہے۔ جو وسیع وجامع نظام اس کتاب میں پایا جاتا ہے، وہ اس زمانہ کے اہل عرب، اہل روم ویونان وایران تو درکنار، اس بیسیویں اور اکیسویں صدی کے علم سائنس کے دعوے داروں میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسفہ وسائنس اور علم عمران کی کسی ایک شاخ کے مطالعہ میں اپنی عمر کھپا دینے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس شعبہ علم کے آخری مسائل کیا ہیں اور پھر جب غائر نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان تمام مسائل کا واضح جواب موجود ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک علم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم کے باب میں صحیح ہے جو کائنات اور انسان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔
چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی عربی زبان کا معیار فصاحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کر دیا تھا حالانکہ اتنی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی طویل مدت تک املا، انشاء ومحاورہ، قواعد زبان اور استعمال الفاظ میں ایک ہی شان پر باقی رہ گئی ہو لیکن یہ صرف قرآن کی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو اپنے مقام سے ہٹنے نہ دیا۔ اس کا ایک لفظ بھی آج تک متروک نہیں ہوا۔ اس کا ہر محاورہ آج تک عربی ادب میں مستعمل ہے۔ اس کا ادب آج بھی عربی کا معیاری ادب ہے اور تقریر وتحریر میں آج بھی فصیح زبان وہی مانی جاتی ہے جو چودہ سو سال پہلے قرآن میں استعمال ہوئی۔
صدیوں سے ہمارے زوال ونکبت اور تنزل وپستی کی سب سے بڑی وجہ اقبال کے الفاظ میں یہ ہے:
وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر
یہ دراصل قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے: وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجورا۔ ’’جب رسول شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔‘‘
دیکھا جائے تو قرآن پاک کی یہ آیت ایک معجزہ ہے اور ایک پیش گوئی بھی۔ اس میں ہمارے اس دور کی ہوبہو تصویر پیش کی گئی ہے۔ دورِ نبوت میں قرآن ہر مسلمان کا حرزِ جاں بنا ہوا تھا۔ ہر کلمہ گو کا شغف وانہماک دنیا میں کسی کتاب سے تھا تو وہ صرف قرآن تھی۔ بد قسمتی سے جوں جوں دورِ نبوت سے دوری ہوتی گئی، مسلمانوں کا انہماک ومشغولیت کتاب اللہ کے بجائے انسانی علوم وفنون اور کتابوں سے بڑھتی گئی۔ خاص طور پر برصغیر میں چونکہ اسلام براہ راست حجاز کے بجائے ایران وترکستان کی راہ سے پہنچا، اس لیے وہاں شروع ہی سے قرآن وسنت کے بجائے عجمی وایرانی علوم وافکار، فلسفوں اور نظریات کا غلبہ رہا۔ اس کے بعد مغل دور میں ہمایوں کے شاہ ایران کے زیر بار احسان ہونے کے بعد تو فلسفہ ومنطق انسانی افکار ونظریات، اسرائیلی داستانوں اور کہانیوں کا بند کھل گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے نصاب تعلیم کا نوے فی صد حصہ انہی انسانی علوم وفنون، فلسفوں اور نظریات کا مرقع رہا ہے۔ قرآن کے حق میں سب سے موثر آوازحضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے بلند کی مگر اس وقت سلطنتِ مغلیہ کے زوال کے بعد علمی مرکز ثقل دہلی سے لکھنو منتقل ہو چکا تھا جہاں مکمل طور پر ایرانی فکر کے حامل شیعی حکمرانی قائم ہو چکی تھی اس لیے ان کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ بد قسمتی سے اب تک ہمارے دینی مدارس میں وہ نصاب تعلیم کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے جس کی اصل بنیاد مشہور ایرانی حکیم وفلسفی فتح اللہ شیرازی نے رکھی تھی جس کا بیشتر حصہ علوم قرآن کے بجائے عجمی فلسفوں، منطق، حکمت وعلم کلام پر قائم ہے جن کا تعلق انسان کے عمل وکردار کے بجائے ذہنی ودماغی ورزش پر ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کی تفسیروں کا تعلق زیادہ تر انہی آیات سے تھا جو امر ونہی پر مشتمل ہیں ۔ اور وہ آیات جن کا براہ راست تعلق انسانی عمل وکردار سے نہیں، ان کی تفصیل میں جانے اور ان کی تعبیر وتفسیر کرنے میں وہ بہت احتیاط سے کام لیتے۔ تفسیر ابن عباسؓ اور تفسیر ابن کعبؓ کا بیشتر حصہ قرآن کے مفرد وغریب الفاظ کی تشریح سے تعلق رکھتا ہے یا آیاتِ احکام کے تعلق سے کوئی حدیث انہیں معلوم ہوئی تو وہ ان آیات کی تشریح وتوضیح میں بیان کر دی جاتی۔ رہے اعتقادی مسائل یا اسرار کائنات تو اس باب میں صحابہ کرامؓ سے بہت کم چیزیں منقول ہیں۔ دور تابعین میں پہلی بار ایرانیوں اور رومیوں کے ساتھ اختلاط کے بعد عجمی افکار کی دخل اندازی اور باطل افکار ونظریات کے سبب سے انتشار ذہنی پیدا ہونا شروع ہوا۔ دوسری طرف یونانی فلسفہ سے لوگ روشناس ہونے لگے۔ تیسری طرف مختلف معاشرتی، معاشی وسیاسی نوعیت کے پیچیدہ مسائل سامنے آئے۔ اس وقت ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کو ذہنی کشمکش اور کج بحثی سے بچا کر براہ راست قرآن وسنت کی اتباع پر ڈالا جائے جس کی بکثرت مثالیں قاضی شریحؒ ، ابراہیم نخعیؒ ، مجاہدؒ ، عطاؒ ، ابن سیرینؒ اور مکحولؒ کے تفسیری نکات میں ملتی ہے۔ اس دور میں نئے مسائل میں اجتہاد کثرت سے ہوا مگر تضاد یا مناظرانہ رنگ پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد تبع تابعینؒ کے دور میں سارے باطل افکار کھل کر سامنے آئے جو اس سے پہلے جھجھکتے ہوئے سامنے آئے تھے۔ ایک طرف سبائیت وخارجیت، رفض واعتزال اپنے اپنے مقاصد کے لیے قرآن وسنت کو استعمال کرنے میں تیز گام ہوئے۔ دوسری طرف یونانی افکار سے متاثر لوگ عوام کے ذہنوں کو مسموم کر رہے تھے اور قرآن کی تفسیر یونانی فلسفہ کے ماتحت کر رہے تھے۔ ان فکری ونظری فلسفوں کے مقابلے پر ابو عمر بن العلاءؒ ، شعبہ بن الحجاجؒ ، سفیان ثوریؒ ، امام مالکؒ ، یونس بن حبیبؒ ، وکیع بن الجراحؒ وغیرہ نے تفسیر بالماثور یا تفسیر بالاحادیث والآثار کر کے لوگوں کو راہ حق پر قائم رکھنے کی کوشش کی لیکن جو لوگ عجمی ایرانی ویونانی افکار سے پوری طرح متاثر ہو چکے تھے، انہوں نے عقلیت، اعتزال اور یونانی فلسفہ واشراق کے رنگ میں تفسیریں کیں۔
غرض تفسیر قرآن میں اصل خرابی اس وقت ہوئی جب اسلامی تہذیب غیر اسلامی تہذیبوں اور افکار وفلسفوں سے دوچار ہوئی تو قرآن کی تفسیر مفسرین کے عقلی شعبدوں کی مینا کاری ہو گئی۔ اس کا آغاز یونانی فلسفہ کی اساس پر ہوا۔ اموی وعباسی خلفا کے دور میں درباروں میں یونان کے حکما سقراط،افلاطون اور ارسطو وغیرہ کی تعلیمات ترجمہ ہو کر پہنچنے لگیں۔ ادھر مسلمان حکما وفلاسفہ نے قرآن پاک کی تعلیمات کو ان یونانی فلاسفہ کے افکار سے مناسبتیں دینی شروع کیں۔ مزید برآں ایران کی زرتشتی تعلیمات اور ہندوستان سے اپنشدوں کے تصورات بعض مسلمان حکما وفلاسفہ کے دماغوں میں جگہ پا گئے۔ تفسیر قرآن میں ان کے تراجم عجمی علم وفن کا نقطہ آغاز تھے۔ اس سے پہلے عرب صرف شاعری سے آشنا تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کی تفسیر میں یونانی وایرانی اور ہندوستانی الٰہیات کا تصور اور اس تصور کے تحت کائنات اور انسان کے متعلق عقلی استدلال راہ پا گیا اور وہ تمام بحثیں قرآن پاک کی تفسیر کا جز ہو گئیں جو قرآن کے مقصد اور دعوت سے خارج تھیں۔ امام رازیؒ اشعری نے جو کچھ لکھا، امام غزالیؒ نے اس باب میں جن خیالات کا اظہار کیا، الجصاصؒ اور زمخشریؒ معتزلی نے تفسیر بالرائے کی جو بنیاد قائم کی، وہ قرآن پاک کی فطرہ وسادہ دعوت وتعلیمات کو اٹھا کر دقیق فلسفیانہ مباحث کے طلسم خانے میں لے گئے جس سے ایک پیچیدہ علم کلام پیدا ہو گیا۔ امام رازی کی معرکہ آرا تفسیر کبیر کے متعلق مولانا آزادؒ لکھتے ہیں:
’’اس میں منطق وفلسفہ، حکمت وعلم کلام وغیرہ سب کچھ ہے مگر قرآن نہیں ہے‘‘
امام رازی خود دنیا کے سارے علوم وفنون کی سیر کے بعد اپنی آخری تصنیف میں قم طراز ہیں:
’’میں نے علم کلام اور فلسفہ کے تمام طریقوں کو خوب دیکھا بھالا لیکن بالآخر معلوم ہوا کہ نہ تو ان میں کسی بیمار کے لیے شفا ہے نہ کسی پیاسے کے لیے سیرابی۔ سب سے بہتر اور حقیقت سے نزدیک راہ وہی ہے جو قرآن کی اپنی راہ ہے۔‘‘
غرض فہم قرآن میں تمام تر الجھاؤ اسرائیلیات اور عقلیات کی بدولت پیدا ہوئے جس کا تصنیفی شاہکار امام فخر الدین رازیؒ کی تفسیر کبیر ہے کہ اس کی بدولت قرآن میں شکوک وایرادات کے دروازے اس طرح کھلے کہ ان کا بند ہونا مشکل ہو گیا۔ اس حقیقت کو علامہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں واشگاف کیا ہے۔
چوں سرمہ رازی من از دیدہ فروئشتیم
تقدیر امم دیدم پنہاں بہ کتاب اندر
علاجِ ضعفِ یقیں ان سے ہو نہیں سکتا
غریب اگرچہ ہیں رازی کے نکتہ ہائے دقیق
غرض قرآن محض عقل نہیں کہ اس کو عقل سے حل کیا جائے۔ قرآن ایک عشق ہے جو اپنی جوت خود جگا لیتا ہے اور قاری وسامع کو مسحور کرتا ہے۔ عقل دلیل دیتی ہے، اعتقاد نہیں دیتی۔ اعتقاد شخصیت سے پیدا ہوتا ہے جو سیرت کو جلا دینی اور عشق کو لطافت بخشتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی ﷺ کی زندگی کو عملی قرآن کہا گیا ہے۔ مولانا ابو الکلامؒ ’’تذکرہ‘‘ میں لکھتے ہیں: ’’قرآن کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے بیضاوی وبغوی کی ورق گردانی نہیں بلکہ دل دردمند کے الہام اور جبرئیلِ عشق کے فیضان کی ضرورت ہے۔‘‘
اور دل دردمند کا الہام اور جبرئیلِ عشق کا فیضان اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم قرآن کو نظر وفکر کی اس زبان میں سمجھیں جو احادیث نبوی اور آثار صحابہؓ اور اقوال تابعین کے سانچے میں ڈھلی ہے اور قرآن ہی کے الفاظ ومطالب کی زبان ہے۔ مولانا آزاد اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے رقم طراز ہیں:
’’قرآن جب نازل ہوا تو اس کے مخاطبوں کا پہلا گروہ ہی ایسا تھا کہ تمدن کے وضعی وصناعی سانچوں میں ابھی اس کا دماغ نہیں ڈھلا تھا۔ فطرت کی سیدھی سادھی فکری حالت پر قانع تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اپنی شکل ومعنی میں جیسا کہ واقع میں تھا، ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ان کے دلوں میں اترتا گیا اور اسے قرآن کے فہم ومعرفت میں کسی طرح کی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ صحابہ کرامؓ جب پہلی مرتبہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت سنتے تھے تو سنتے ہی اس کی حقیقت کو پالیتے تھے لیکن صدر اول کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ روم وایرن کے تمدن کی ہوائیں چلنے لگیں اور پھر یونانی علوم کے تراجم نے انسانی علوم، فنون وضعیہ کا دور شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جوں جوں وضعیت کا دور بڑھتا گیا، قرآن کے فطری اسلوب سے طبیعتیں ناآشنا ہوتی گئیں۔ رفتہ رفتہ وہ وقت آ گیا کہ قرآن کی ہر بات وضعی وصناعی طریقوں کے سانچوں میں ڈھالی جانے لگی۔ چونکہ ان سانچوں میں وہ ڈھل ہی نہیں سکتی تھی اس لیے طرح طرح کے الجھاؤ پیدا ہونے لگے اور جس قدر کوششیں سلجھانے کی کی گئیں، الجھاؤ اور زیادہ بڑھنے لگا۔‘‘
آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور سے قرون آخر تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے، ان کا طریق تفسیر ایک روبہ تنزل معیارِ فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر پچھلی کڑی پہلی کڑی سے پست تر ہے اور ہر سابق لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جس قدر اوپر کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، حقیقت زیادہ واضح، زیادہ بلند اور اپنی قدرتی شکل میں نمایاں ہوتی جاتی ہے اور جس قدر نیچے اترتے ہیں، حالت برعکس ہو جاتی ہے۔ یہ صورت حال فی الحقیقت مسلمانوں کے عام دماغی تنزل کا قدرتی نتیجہ تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کی بلندیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کوشش کی کہ قرآن کو اس کی بلندیوں سے نیچے اتار لیں کہ ان کی پستیوں کا ساتھ دے سکے۔‘‘
بقول اقبال:
خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق
ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب
کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق
اس اعتبار سے قرآن دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں:
’’علما روایت پسند ہوئے تو اسرائیلیات کا شکار ہوئے اور علما عقلیت پسند ہوئے تو یونانیوں کے مزعومات کے اسیر وپابند۔ تمام علماء اسلام میں علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم ہی دو بزرگ ہیں جو ایک طرف روایات کے ناقد ومبصر ہیں تو دوسری طرف یونانی فلسفیات کے نقاد اور ان کے حق وباطل کے واقف کار اور ان کے دل ان سب سے ماورا حکمت محمدی کے ذوق چشیدہ اور ان کے سینے معارف نبوی ﷺ کے گنجینہ ہیں۔ ان کی تفسیر تمام تر حکمت ومصلحت اور حقیقت ومغز پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ حکمت نہیں جو یونان کے صنم کدہ سے اچھلی ہے بلکہ وہ جو حجاز کی نہر کوثر سے بہہ کر نکلی ہو یا جو فطرت انسانی کے ربانی چشموں سے ابلی ہو۔‘‘
جس طرح گزشتہ دور میں مسلمانوں کی علمی تباہی کا راز قرآن کو چھوڑ کر فلسفہ یونان کی دماغی پیروی میں تھا، اسی طرح آج مغربی فکر وتمدن کی اندھی تقلید میں ہے۔ انسان قرآن کی روح تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جب اسرائیلیات وعقلیات اور موجودہ مغربی فکر وفلسفہ کی ذہنی آلودگیوں سے دور رہ کر قرآن کو اس کے اپنے ماحول، زبان اور احادیث وآثار کی روشنی میں دیکھے۔ آج قرآن کا مقابلہ بائبل یا تورات سے نہیں اور نہ اس کی ٹکر ہندومت یا بدھ مت ومجوسیت وغیرہ سے ہے بلکہ اسلام کا مقابلہ آج یورپ کے سائنسی وعلمی نظریات وافکار سے ہے جن میں نئی نسل کے لیے ایسا سحر ہے کہ جب تک ان کو مطمئن نہ کیا جائے ہم نئی نسل کو اس سحر سے نہیں نکال سکتے۔ آج یورپ کا ضمیر پھر اصل فطرت اور مذہب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے مگر قرآن کے حامل صدیوں سے فلاسفہ یونان کی بھول بھلیاں کے اسیر بن چکے ہیں۔
قرآن کا مخاطب صرف مسلمان نہیں بلکہ نوع انسانی ہے۔ وہ خدا، انسان اور کائنات کے باہمی رشتہ کی گرہ کشائی کرتا ہے۔ وہ انسان کو ایسے اصول اور دستور حیات عطا کرتا ہے جس سے انسانی فکر وعمل میں کوئی کجی نہ رہے۔ قرآن انسانیت کے لیے فلاح وسعادت کی راہ کھولتا ہے اور وہ اپنے خالق کے متعلق انسان کی ابدی جستجو اور اس سارے سفر کی آخری منزل کا سنگِ میل ہے۔ انسان قرآن کی رہنمائی کے بغیر نہ تو اپنے خالق کا صحیح تصور کر سکتا ہے، نہ اپنی ذات کی معرفت۔ دنیا کے اکثر مذاہب اور قوموں نے اللہ کے تصور کو اپنے حصار میں بند کر لیا ہے اور خدا کو صرف اپنا ہی معبود گردانا ہے لیکن قرآن نے خدا کے رب العالمین ہونے کا اعلان کیا ہے۔ قرآن سے پہلے تک دنیا کی قوموں میں خدا کا تصور خوف ودہشت کا تصور تھا، قرآن نے رحمت وعدالت کا تصور پیش کیا ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ایک عالمی منشور ہے۔ یہ ان لوگوں کی جستجو اور اضطراب کا فطری جواب ہے جو اپنے خالق ورب کی تلاش میں عقل وفکر کے صحراؤں اور بیابانوں میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآن سے پہلے جو کتب سماوی تھیں وہ انسانیت کے لیے بمنزلہ ابتدائی نصاب کے تھیں اور قرآن ایک بالغ، باشعور اور ترقی یافتہ معاشرہ کے لیے مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ قرآن ایک بے مثل سچائی ہے جو کائنات، انسان اور خدا کے باہمی رشتہ کو حرف آخر کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا اور اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کائنات کی تکوین کیونکر ہوئی؟ انسان ربوبیت کاملہ کا مظہر ہے۔ قرآن تمام سچائیوں کی جامع آخری آسمانی دستاویز ہے۔ وہ ایک ضابطہ ہے جس پر چل کر انسان رشد وہدایت اور سعادت حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ خالق کی حقیقت، کائنات کی غایت، انسان کی تخلیق کے مقصد، نبوتوں کے مشن، جزا وسزا کے قانون اور حق وباطل کے امتیازات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کی تعلیم ٹھیک ٹھیک دلوں میں اتر جاتی ہے اور انسان یقین کی اس دولت کو پا لیتا ہے جو فلسفہ کے سفر میں شک کے کانٹوں سے تلووں کو زخمی کرتی اور اضطراب کے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ سائنس کی خانہ ویرانی کا بھی یہی عالم ہے۔ وہ ثبوت دیتی ہے مگر یقین نہیں دیتی۔ انسانی روح کی منزل مقصود یقین ہے۔ جب تک اس کو یقین حاصل نہ ہو وہ کائنات کے توے پر اسپند کے دانے کے مانند تڑپتا رہتا ہے۔ انسانی زندگی یقین کے بغیر جان کنی کی زندگی ہے اور یقین کی دولت صرف قرآن عطا کرتا ہے۔
قرآن سے لطف اندوز ہونے اور استفادہ کرنے اور فہم قرآن کے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ طویل طویل تفاسیر کے بجائے محض ترجمہ سمجھنے پر اکتفا کیا جائے اس لیے کہ ہر دور میں قرآن کی جو تفسیریں کی گئی ہیں، ان میں مفسر کے ذہن وفکر پر جس پہلو کا غلبہ تھا، اس کا عکس آ گیا یا دور کے رجحانات وتقاضوں کا۔ اس لیے قرآن کی زیادہ ضخیم وبسیط تفاسیر کے بجائے صرف قرآن کے ترجمہ یا مختصر ترین توضیح کو ترجیح دی جائے جیسے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلویؒ کے حواشی ہیں کیونکہ زیادہ طویل وعریض تفاسیر سے انسان خالق کے بجائے اپنی ہی جیسے دوسرے انسانی کلام میں مشغول ہو کر قرآن اور اللہ کے بجائے انسانی ذہن وفکر سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے دینی نصاب تعلیم کے متعلق اپنے وصیت نامہ میں یہ لکھا کہ قرآن کا ترجمہ بغیر تفسیر کے ختم کرنا چاہئے۔ پھر اس کے بعد تفسیر جلالین بقدر درس پڑھائی جائے۔ جلالین قرآن کی مختصر ترین تفسیر ہے جس کے الفاظ تقریباً قرآن کے الفاظ کے برابر ہیں۔ لمبی لمبی تفاسیر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو کسی مخصوص شخص کے فکر ونظر کی عینک سے دیکھنے لگتا ہے۔ گویا کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے پہلے کسی انسان کے ذہن وفکر پر ایمان لایا جائے۔ انسان قرآن کا صحیح لطف، اس سے استفادہ اور برکات اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ قرآن کے الفاظ یا زیادہ سے زیادہ اس کے ترجمہ تک محدود رہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوریؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شجر کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہوئے تھے، انسان قرآن پڑھتے وقت اپنے کو شجر تصور کرے پھر اپنے میں سے نکلے ہوئے الفاظ کو یوں سمجھے کہ خدائے پاک ہم کلام ہیں اور میں براہ راست سن رہا ہوں۔ مولانا محمد علی مونگیریؒ بانی ندوۃ العلما فرماتے ہیں کہ میں نے ابتداء اً حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے عرض کیا، حضرت مجھ کو جو مزہ شعر میں آتا ہے قرآن شریف میں نہیں آتا۔ فرمایا ابھی بُعد ہے۔ قُرب میں جو مزہ قرآن شریف میں ہے کسی چیز میں نہیں۔ کثرت سے قرآن شریف پڑھا کرو۔ اللہ میاں دل پر آکر بیٹھ جاتے ہیں۔
قرآن کی تفہیم اور اسے بآسانی سمجھنے اور کسی موضوع پر حکم خداوندی معلوم کرنے کے لیے ہمارے مکرم پروفیسر محمد شریف بقا صاحب نے تقریباً ۱۶۵ عنوانات یا موضوعات مقرر کر کے ہر ہر موضوع پر آیات قرآنی مع ترجمہ کے درج کر دی ہیں۔ اب معمولی اردو پڑھا لکھا شخص بھی کسی موضوع پر بآسانی حکم خداوندی معلوم کر سکتا ہے۔ ’’قرآنی موضوعات‘‘ نہ صرف عام مسلمان کے لیے بلکہ سکالرز، علما اور علمی کام کرنے والوں کے لیے بھی بیش قیمت تحفہ ہے۔ اب کسی درپیش موضوع پر چند لمحات میں ہر شخص قرآن پاک میں موجود تمام آیات کا احصا کر سکتا ہے اور کسی موضوع پر قرآن پاک میں بکھری ہوئی آیات پر یکجا نظر ڈال کر قرآن حکم اور منشاے خداوندی معلوم کر سکتا ہے۔ اگرچہ عربی میں اس موضوع پر متعدد حضرات نے کام کیا ہے مگر اردو میں اپنے انداز کا منفرد اور قابل صد ستائش کام ہے جس پر پروفیسر محمد شریف بقا صاحب بجا طور پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔ کتاب باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ عمدہ کمپوزنگ، خوبصورت طباعت، مضبوط جلد اور حسین سرورق کے ساتھ ظاہری طور پر بھی نہایت دیدہ زیب بن گئی ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر لائبریری، ہر مسجد اور ہر گھر کی زینت بنے اور گھر کے افراد جمع ہر کر سبقاً سبقاً پڑھیں تاکہ ہمارا قرآن سے ربط وتعلق قائم ہو۔ اس کی برکات سے ہماری زندگیاں منور ہوں اور حشر کے روز قرآن ہمارا مضبوط سفارشی بنے۔ وآخردعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تعلیمی نصاب کی ضروریات ۔ سلطان اورنگ زیب عالمگیرؒ کی نظر میں
پروفیسر عشرت جاوید
جب اورنگ زیب (۱۶۵۸ء۔۱۷۰۷ء) ہندوستان کی گدی پر بیٹھے تو ایک دن ان کے استاد ملا محمد صالح ان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر لائے تاکہ کچھ انعام واکرام پائیں لیکن عالمگیر جیسے متقی اور پرہیز گار شخص اپنی مدح وستائش سے خوش ہونے والے نہیں تھے۔
استا دنے کہا :’’جہاں پناہ، میں کچھ لکھ کر لایا ہوں۔‘‘
’’غالباً کوئی قصیدہ لکھ کر لائے ہوں گے‘‘، عالمگیرؒ نے قیاس سے کہا۔
’’جی ہاں، میں ایک قصیدے پر آ پ سے دادِ تحسین کا طلب گار ہوں۔‘‘
’’اس قصید ے میں میری تعریف ہوگی؟‘‘، اورنگ زیب نے پوچھا۔
ملا صالح نے مسکرا کر کہا: ’’آپ کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے۔ ہاں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔‘‘
عالمگیرؒ نے کہا: ’’استاذ محترم، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ہم اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے۔ آپ ہمارے استاد ہیں۔ آپ کا ہم پر حق ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آ پ کی مدد کریں۔ آپ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہماری جھوٹی سچی تعریف کر کے کچھ حاصل کریں۔‘‘
یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اتنا اتنا دے دیا جائے۔
جو کچھ دیا گیا، وہ ان کی توقعات سے بہت کم تھا۔ اپنی سلطنت کو عمر فاروق، علی مرتضٰی، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اور ناصر الدینؒ کے انداز پر چلانے کی کوشش کرنے والے عالمگیر سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بیت المال کی آمدنی کو بے دریغ خرچ کریں۔ جو شخص دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک ہو کر خود قرآن لکھ کر اور ٹوپیاں کاڑھ کر روزی کماتا ہو، وہ بیت المال کا سرمایہ کسی کی خوشنودی کے لیے کس طرح لٹا سکتا تھا۔
ملا محمد صالح نے یہ انعام واکرام اپنی توقعات سے کم دیکھا تو کہا، ’’جب آپ میرا حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ مجھے عطا کیا جا رہا ہے، وہ میرے حق سے بہت تھوڑا ہے۔‘‘
عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو چہرہ سرخ ہو گیا لیکن انہوں نے استاد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت متانت وسنجیدگی سے کہا:
’’استاد محترم! اگر حق کا سوال ہے کہ تو ہم بھی ذرا زیادہ وضاحت اور صاف گوئی سے کام لیں گے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ نے ہمیں تعلیم دی لیکن اس بات میں کلام ہے کہ آپ نے جو تعلیم ہمیں دی تھی، وہ صحیح تھی۔ شاید آپ دربار میں کوئی عہدہ چاہتے ہوں گے یا جاگیر کے متمنی ہوں گے۔ ہم ضرور عہدہ بھی دیتے اور جاگیر بھی بشرطیکہ آپ ہمارے قلب کو شائستہ تعلیم سے منور ومعمور کرتے۔ آپ نے ہماری قیمتی عمر عربی صرف ونحو سکھانے میں برباد کی یا فلسفہ کے لایعنی اور لغو مسائل سے ہمارا دماغ پریشان کیا۔ آپ نے ہمیں ایسی تعلیم دی جس سے دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا۔ آپ نے ہماری نوعمری کا وہ بیش قیمت وقت لغو باتوں اور بے سود اور بے لطف الفاظ سیکھنے سکھانے میں تلف کر دیا جو نہایت کارآمد باتیں سیکھنے میں صرف ہو سکتا تھا۔ آپ نے یہ نہ سمجھا کہ بچپن کا زمانہ ایسا ہوتا ہے جب حافظہ قوی ہوتا ہے۔ ہزاروں مذہبی اور عقلی احکام آسانی سے ذہن نشین ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ایسی تعلیم ہو سکتی ہے کہ دل ودماغ میں اعلیٰ درجہ کے خیالات پیدا ہوں، حوصلے بڑھیں، بڑے بڑے کام کرنے کی قابلیت آئے۔
آپ نے سالہا سال تک عربی صرف ونحو کی تعلیم دی، حالانکہ اس کے لیے صرف ایک سال کافی تھا۔ پھر آپ نے فلسفہ پڑھایا جس کے مسائل توہمات بڑھاتے ہیں۔ ایسے مشکل اور ادق ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں اور آسانی سے دماغ سے محو ہو جاتے ہیں۔ جن کا نتیجہ کچھ نہیں، اگر ہے بھی تو صرف اتنا کہ دماغ پراگندہ ہو جائے اور عقل چکرا جائے۔ آدمی منہ پھٹ، زبان دراز، ہٹ دھرم اور بد اعتقاد بن جائے۔ ایسی لا یعنی گفتگو کرنے لگے کہ لوگ تنگ آ جائیں۔ بتائیے کیا آپ نے ہمیں فلسفی نہیں بنایا؟ ....... کیا میرے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے قرآن شریف حفظ کر لیتا، ایک سال میں اتنی عربی پڑھ لیتا کہ اس میں گفتگو کر سکتا۔ پھر آپ نے کیوں میری عمر کا بہترین زمانہ برباد کیا؟
آپ نے مجھے بتایا کہ سارا افرنگستان (Europe) ایک جزیرے سے بڑا نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ طاقتور کسی زمانے میں پرتگال کا بادشاہ تھا، اس کے بعد ہالینڈکا بادشاہ ہوا اور اب انگلینڈ کا بادشاہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ فرانس کا بادشاہ اور انڈونیشیا کا بادشاہ ہمارے باج گزار کسی راجہ کے برابر ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا---- اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں----کشور ہندوستان اور سارے جہاں کے بادشاہ ہیں۔ کیا آپ کی تاریخ وجغرافیہ دانی اسی قدر تھی کہ جن باتوں کو آپ نہیں جانتے تھے، انہیں غلط طریقہ پر مجھے بتائیں؟
استاذ محترم! آپ کا یہ فرض تھا کہ مجھے دنیا کے ہر حصے کے جغرافیہ سے آگاہ کرتے، یہ بتاتے کہ کون سا ملک کہاں واقع ہے، ان کی قدرتی حفاظت کے کیا ذرائع ہیں، کہاں کیا پیدا ہوتا ہے، کس چیز کی کانیں کس ملک میں ہیں، کس ملک میں کتنا بڑا دن ہوتا ہے اور کتنی بڑی رات، کس ملک میں بارش کب اور کیوں ہوتی ہے، کس قوم کے آئین جنگ کیا ہیں، سمندر کی وسعت کیا ہے، اس میں جزیرے کہاں کہاں ہیں اور کتنے، پہاڑوں کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور ان کے کیا فائدے ہیں، موسم کے بدلنے کی کیا وجوہ ہیں، کس بات کی احتیاط لازم ہے۔ آپ مجھے تاریخ پڑھاتے اور بتاتے کہ کس قوم نے کیسے ترقی کی اور اس کی تنزلی کے کیا اسباب ہوئے، کس بادشاہ نے فتوحات کیسے اور کتنی حاصل کیں، اور کن حادثوں سے اس کی سلطنت تباہ ہوئی، اس کا آئین حکمرانی کیا تھا اور آمدنی کے وسائل کیا تھے۔ آپ ان حادثات اور انقلابات سے ہم کو واقف کرتے جن سے قومیں یا سلطنتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ افسوس آپ نے ہم کوبنی آدم کی وسیع اور کامل تاریخ سے آگاہ نہ کیا ۔ اور تو اور، ہمارے نامور بزرگوں کے نام تک بھی نہ بتائے۔ ان کے حالات سے آگاہ نہ کیاجو سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نے ان کی سوانح عمریوں کا کوئی تذکرہ نہ کیا جنہوں نے اپنی خداداد ذہانت اور شجاعت سے عظیم الشان فتوحات حاصل کیں حالانکہ ایک شاہزادے کے لیے ان باتوں کا جاننا ضروری تھا۔ تاریخ ہی ایک ایسا علم ہے جس سے عقل بڑھتی ہے اور دل ودماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ بتائیے آپ نے مجھے کیا سکھایا، مجھے آپ کا کس قدر احسان مند ہونا چاہیے؟
کاش، آپ مجھے ایسا سبق پڑھاتے جس سے انسان کے نفس کو ایسا شرف وعلو حاصل ہو جاتا کہ دنیا کے انقلابات سے متاثر نہ ہوتا۔ ترقی اور تنزلی کی حالت میں ایک سا ہی رہتا۔ نہ ترقی کی خوشی ہوتی نہ تنزلی کا غم۔ آپ مجھے ایسے استدلال کا عادی بناتے کہ تصورات او ر تخیلات کو چھوڑ کر ہمیشہ اصول صادقہ کی جانب رجوع کیا کرتا اور علم دین کے حقائق سے مجھے مطلع کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کا ایسا احسان مانتے جیسا سکندر نے ارسطو کا مانا تھا۔ ہم ارسطو سے زیادہ آپ کی عزت کرتے اور سکندر سے زیادہ آپ کو انعام دیتے۔
ملا جی ! آپ نے تو ہم کو یہ بھی نہ بتایا کہ ایک بادشاہ کو رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے۔ ہم ایک شہنشاہ کے فرزند تھے۔ ضرورت تھی کہ آپ ہم کو جہاں بانی کے آئین سکھاتے، فنون حرب کی تعلیم دیتے، صف آرائی کا طریقہ سکھاتے، لشکر کو ترتیب دینے اور قلعوں کو توڑنے کی تعلیم دیتے۔ آپ نے تو ہمیں سب باتوں سے ناواقف رکھا۔ اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتی اور ہم اپنے فہم وذکا سے خود ہی کچھ نہ سیکھ لیتے تو آج بالکل کورے ہوتے اور کچھ بھی نہ کرسکتے۔ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمارے رب کا احسان ہے۔ اس پاداش میں کہ تم نے ہماری نوعمری کا بہترین زمانہ فضول باتوں میں ضائع کیا، تم سے سختی سے بازپرس کی جائے تو کچھ بے جا نہ ہوگا۔‘‘
عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خیالات سن کر جتنے بھی علما اور امرا حاضر تھے، سب دنگ رہ گئے۔ استاد کے فرائض، اس کی تعلیم، معیار، فلسفہ کے متعلق عالمگیرؒ کا نظریہ اصلی اور حقیقی تعلیم کی تحصیل کا خیال کتنا وسیع تھا، اس سے نہ صرف سب لوگ حیران ہوئے بلکہ شرمندہ بھی ہوئے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اساتذہ کی اس کمی کا بڑا درد تھا
شکایت ہے مجھے یا رب ! خداوندان مکتب سے
سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا
(ماخوذ از ’’پراسرار بندے‘‘، مطبوعہ طیب اکیڈمی، ملتان)
مسیحیوں اور مسلمانوں کے خلاف یہودی سازش
عطأ الحق قاسمی
پاکستان میں ایک عرصے سے ’’را‘‘ اور ’’موساد‘‘ مل کر جو تخریبی کارروائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے بہاول پور کے چرچ میں اپنی عبادت میں مصروف مسیحیوں پر فائرنگ کی واردات پہلی واردات ہے جو ان کے مذموم مقاصد کے نقطہ نظر سے بھرپور ہے۔ اس سے پہلے اہل سنت اور اہل تشیع کی مساجد میں نمازیوں پر فائرنگ ہوتی رہی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے ان دو بڑے فرقوں میں فسادات کرانا تھا مگر ان وارداتوں کا الٹا اثر ہوا۔ ان دونوں فرقوں کے عوام مشتعل ہو کر گلی کوچوں میں باہم دست وگریباں ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ باری باری ایک دوسرے کی مساجد پر فائرنگ کرنے والا گروہ ایک ہی ہے اور وہ دونوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ اگر دشمن کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو پورے ملک میں شیعہ سنی فسادات کی آگ بھڑک اٹھتی مگر خدا کا شکر ہے کہ ہر بار فائرنگ کے بعد دشمن فسادات کا انتظار کرتا رہا اور اسے کہیں سے کبھی کوئی ’’اچھی‘‘ خبر نہ مل سکی۔
اس محاذ سے مایوس ہو کر اب دشمن ہمارے مسیحی بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا ہے اور اس نے سولہ مسیحیوں کو چرچ میں سروس کے دوران اندھا دھند فائرنگ سے بھون کر رکھ دیا۔ اس نے انتہائی خطرناک موقع پر انتہائی خطرناک کھیل کھیلا۔ وہ اس سے بیک وقت کئی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک مقصد مسیحی اور مسلمان بھائیوں کے درمیان منافرت کی دیوار کھڑی کرنا ہے تاکہ ان میں موجود باہمی دوستی اور محبت کی فضا کو باہمی نفاق میں تبدیلی کیا جا سکے اور یوں پاکستان کے ان سپاہیوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر کے پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ یہودی آغاز اسلام سے ہی مسلمانوں اور مسیحیوں کو ایک دوسرے سے بھڑانے کے لیے کوشاں رہے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں بار بار یہودیوں کو سازشیں کرنے پر متنبہ کیا گیا ہے مگر یہ گروہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آیا۔ اس کے اسی سازشی کردار کی بنا پر دنیا کے مختلف ملکوں میں انہیں مار پڑی اور ان کی موجودہ مضبوط پوزیشن کے باوجود مستقبل میں بھی ان کی درگت یقینی نظر آتی ہے۔
افغانستان پر امریکی حملوں کے حوالے سے پاکستانی حکومت نے جو ’’کردار‘‘ اپنایا ہے، اس پر اسے ڈالروں میں ’’ویلیں‘‘ مل رہی ہیں اور ’’دہشت گردی‘‘ کے خلاف ’’عالمی اتحاد‘‘ میں شامل ہونے پر مغربی ممالک ’’شاباش‘‘ الگ دے رہے ہیں جب کہ بھارت اور اسرائیل پاکستان کو بہرصورت ایک ایسا دہشت گرد ملک ثابت کرنا چاہتے ہیں جہاں ’’جنونی مسلمان‘‘ رہتے ہیں۔ چرچ میں بے گناہ مسیحیوں پر فائرنگ کر کے را اور موساد نے مغربی مسیحی ممالک کو یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس گھٹیا اور غلیظ حرکت کا ایک مقصد امریکی بمباری سے ہلاک اور زخمی ہونے والے معصوم بچوں کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانا بھی ہے اور شاید ایک مقصد پاکستانی حکومت پر دباؤ بڑھانا بھی ہے تاکہ اگر وہ کسی پوائنٹ پر کمپرومائز کے لیے تیار نہ ہو تو اسے اس کے لیے بھی تیار کیا جا سکے۔
ان تمام امور کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ کو اپنی اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے اور متوقع پراپیگنڈے کا توڑ کرنا چاہیے۔ اندرون ملک علما نے بروقت اس دہشت گردی کی پرزور مذمت کی ہے اور مسیحی رہنماؤں نے بھی تدبر اور بردباری کا ثبوت دے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہیں۔ وزیر مذہبی امور اور وزیر اقلیتی امور نے بہاول پور جا کر پس ماندگان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ بہت ہی اچھا ہو اگر قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمن، مولانا نورانی اور مولانا سمیع الحق کے علاوہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی لواحقین سے اپنی دلی ہم دردی کا اظہار لواحقین کو اپنے سینے سے لگا کر کریں۔ مسیحی ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کے دکھ درد میں شامل ہونا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔
(بشکریہ روزنامہ جنگ لاہور)
ارباب علم ودانش کے لیے لمحہ فکریہ
ابو سلمٰی
۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ میں پاک فوج کی شجاعت کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیل گئی جس سے عالم اسلام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ۱۹۶۷ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے پاکستان کو دشمن نمبر ایک کہا اور اس کے خلاف خفیہ سازش شروع کر دی جو سقوط ڈھاکہ کی صورت میں نمودار ہوئی۔
۱۹۷۱ء کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں اور عوامی لیگ نے مغربی پاکستان میں کوئی امیدوار نامزد نہیں کیے۔ دونوں جماعتوں نے سیاسی حقوق کی پامالی اور مالی بحران کے الزامات ایک دوسرے پر عائد کیے تو صوبائی تعصب اسلامی رشتے پر غالب آ گیا۔ دونوں جماعتیں بھاری اکثریت سے اپنے اپنے صوبوں میں کامیاب ہوئیں۔ خفیہ ہاتھوں نے اقتدار کی خاطر دونوں کو ہٹ دھرمی کا لقمہ دیا۔ اقتدار کی جنگ جس دور میں شروع ہوئی، اس وقت وطن عزیز میں فوجی حکومت تھی۔ طاغوتی عناصر نے وطن عزیز کی فوجی قیادت سے انتقام بھی لے لیا اور اس کے کردار کو پاکستان کے عوام اور عالم اسلام میں رسوا بھی کر دیا۔
اس کے بعد مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں صوبائی تعصب ابھارنے کے لیے علاقائی پارٹیاں معرض وجود میں آ گئیں تو صوبائی خود مختاری کے مطالبے منظر عام پر آ گئے۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں سندھو دیش، کراچی کو الگ صوبہ، سرحد میں پختونستان، بلوچستان میں مرکز کے خلاف آہ وپکار، جنوبی پنجاب میں سرائیکی صوبے کا مطالبہ اور پنجاب بھر میں ’’جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ‘‘ کے نعرے لیڈروں کی زبان سے نکل کر عوام میں پھیل گئے۔
وطن عزیز کے محب وطن عناصر کی مساعی جمیلہ سے مغربی پاکستان کے صوبوں میں مشرقی پاکستان کی طرح خانہ جنگی کے حالات پیدا نہ ہو سکے۔ البتہ پاکستان نے جس کے نادیدہ اشارے پر روسی فوج کو افغانستان سے بھگانے میں اہم کردار ادا کیا، اسی صہیونی قوت کی ہٹ لسٹ پر سرفہرست آ گیا اور پاکستان کو نامور فوجی جرنیلوں کی قیادت سے محروم کر دیا گیا۔
پھر وطن عزیز میں جمہوری حکومتوں کے یکے بعد دیگرے شارٹ ٹرم سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران میں اسلام نافذ ہوا اور نہ عوام کے روزہ مرہ زندگی کے مسائل حل ہوئے بلکہ مسلسل مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی تو لوگ جمہوری نظام سے بھی مایوس ہو گئے۔
معاہدۂ واشنگٹن کی وجہ سے پاک فوج کی کارگل کی چوٹیوں سے پسپائی اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے افغانستان پر امریکی حملے سے عوام میں حکومت کے خلاف نفرت کے جذبات ابھر آئے تو اسلامی انقلاب کے داعی جولائی ۹۹۹ء۱ میں منظر عام پر آ گئے۔ آب پارہ چوک اور مسجد شہدا میں عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اس کا بین ثبوت ہے۔
جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو مذہبی قیادت کو برسراقتدار آنے سے روکنے کے لیے صہیونی قوت کون سالائحہ عمل اختیار کرتی ہے؟ امریکی سی آئی اے کے تجزیہ نگار گراہم ای فلر کی رپورٹ کی آخری شق پیش خدمت ہے:
’’فوج کو اسلامی تحریکوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جائے اور جب یہ دیکھا جائے کہ ان ممالک میں اسلامی اور مسلم تشخص رکھنے والی کوئی سیاسی جماعت اور اس کا قائد عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کا تارا بن چکا ہے اور عوامی حمایت اور تعاون کا سیلاب بلا خیز اسلامی تشخص اور پس منظر رکھنے والی سیاسی جماعت کے قائد کے اشاروں کا منتظر ہے اور وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ اسلام پسند عوامی قوت کا سیلاب سیکولر اور مغربیت زدہ حکمرانوں کی حکومتوں کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گا تو فوجی انقلاب کے ذریعے سے حکومت کا دھڑن تختہ کروا دیا جائے اور اسلام پسند قوتوں کا راستہ روک دیا جائے۔‘‘ (ہفت روزہ چٹان، لاہور ۔ ۳۱ اگست ۱۹۹۴ء۔ بحوالہ رواداری اور مغرب ص ۲۸۰)
اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے فلر کی ترکیب پر عمل کیا گیا۔ ایک کو سبک دوش کرنے اور دوسرے کو قبضہ کرنے کا اشارہ دے کر عراق، کویت کا ڈرامہ دہرایا گیا۔
پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اسماعیلی اسٹیٹ بنانے کی سرگرمیاں پہلے ہی سے جاری تھیں کہ اچانک گوجرانوالہ کو عیسائی اسٹیٹ اور سیالکوٹ شکر گڑھ کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کی خبروں کا ایک دن اخبار میں شائع ہونا اور دوسرے دن تردید اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ فکر دامن گیر ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ضلعی حکومتیں قائم کرنے کی پالیسی نے یہ معما حل کر دیا۔ مسلم پاکستانی کے بجائے سندھی، پنجابی کی صوبائی پہچان معروف تھی۔ اب اس کا گراف سیالکوٹی، ملتانی ضلعی سطح پر آ جائے گا۔ پھر یہ خبریں منظر عام پر آئیں گی کہ ہمارا ضلع معدنیات سے مالا مال ہے، کوئی کہے گا کہ ہمارا ضلع زرعی پیداوار میں خود کفیل ہے۔ پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں مرکز سے کچھ نہیں ملتا۔ یہی نفرت کے جذبات ضلعی خود مختاری کے مطالبے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا نخواستہ ضلعی حکومتوں کو غیر مسلم این جی اوز سے براہ راست قرضے لینے کے معاہدے کرنے کا اختیار مل گیا تو تعمیر وترقی کی آڑ میں ضلعی حکومتیں قرضوں کی دلدل میں پھنس جائیں گی۔ پھر وہی ہوگا جو این جی اوز آرڈر دیں گی۔
پھر کیا ہوگا؟ گوجرانوالہ میں عیسائیوں اور سیالکوٹ میں مرزائیوں کو آباد کرنے کی مہم شروع ہو جائے گی۔ پھر ضلعی خود مختاری کا مطالبہ شدت اختیار کر جائے گا تو یہ معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچے گا اور این جی اوز کو اقوام متحدہ سے استصواب رائے کی قرارداد پر عمل کرنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس دوران میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مقبوضہ کشمیر یا کسی ایک حصے میں استصواب رائے کی قرارداد پر عمل ہوا تو مستقبل میں اقوام متحدہ کو اپنی نگرانی میں پاکستان کے اندر ضلعی خود مختاری کی قرارداد پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی عالم اسلام کی ایٹمی قوت کو ریزہ ریزہ کرنے کی سازش ہے اور مرزائیوں کا اکھنڈ بھارت قائم کرنے کا خواب ہے اور ۲۰۲۵ء تک اسلام کو مغلوب کرنے کے صہیونی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ کس دور میں شروع ہوا؟ طریقہ واردات کیا ہے۔ ارباب علم ودانش کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
(بشکریہ ہفت روزہ الاعتصام لاہور)
ورلڈ اسلامک فورم کا سالانہ اجلاس
ادارہ
ورلڈ اسلامک فورم کی مرکزی کونسل نے افغانستان کے خلاف امریکہ کی جنگ کو مغربی تہذیب وثقافت کی بالادستی قائم کرنے اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنے کی جنگ قرار دیتے ہوئے جنگ کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ لیگ آف نیشنز کی طرح اقوام متحدہ بھی عالمی امن کے قیام میں ناکام ہو گئی ہے اس لیے اسے ختم کر کے موجودہ معروضی عالمی حقائق کی بنیا دپر اقوام عالم کے درمیان ایک نئے معاہدے اور اشتراک کی راہ ہموار کی جائے۔
مرکزی کونسل کا سالانہ اجلاس ۴ نومبر کو جامع مسجد سٹینلی روش آکسفورڈ میں ورلڈ اسلامک فورم کے چیئرمین مولانا محمد عیسیٰ منصوری کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں مولانا زاہد الراشدی، مفتی برکت اللہ، طٰہٰ قریشی، مولانا رضاء الحق سیاکھوی ، مولانا قاری عمران جہانگیری، مولانا محمد اکرم ندوی، مولانا محبوب الٰہی، مولانا محمد قاسم، مولانا محمد ریاض اور جناب مسرور احمد نے شرکت کی۔
فورم کے سیکرٹری جنرل مولانا رضاء الحق سیاکھوی نے اجلاس میں فورم کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ورلڈ اسلامک فورم کا بنیادی مقصد عالم اسلام کے مسائل کی طرف اصحاب علم وفکر اور علمی ودینی مراکز کو توجہ دلانا اور ان کے حل کے لیے علمی وفکری جدوجہد کرنا ہے جس کے لیے مختلف جماعتوں اور راہ نماؤں کے ساتھ رابطوں اور ملاقاتوں کے علاوہ خصوصی اجتماعات اور مجالس کا انعقاد کیا گیا اور بعض کتابچے اور مضامین بھی شائع کیے گئے تاہم جو کچھ ہونا چاہئے تھا، اس کا اہتمام نہیں ہو سکا اور آئندہ اس کی تلافی کی جائے گی۔
اجلاس میں افغانستان کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا اور ایک اعلامیہ میں کہا گیا کہ امریکہ اس جنگ کے ذریعے سے افغانستان کی اسلامی نظریاتی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک کی اسلامی تحریکات کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہے اور وسطی ایشیا میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پر قبضہ کرنے کا عرصہ سے خواہش مند ہے لیکن وہ اپنی جنگ کے اصل مقاصد کے اظہار کی اخلاقی جرات سے محروم ہے اور اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا عنوان دے کر دنیا کو دھوکا دے رہا ہے اس لیے یہ جنگ دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا پر مغربی تہذیب وثقافت کی بالادستی قائم کرنے اور معاشی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے اور اسے فی الفور بند ہونا چاہیے۔
اعلامیہ میں اقوام متحدہ کے کردار کو انتہائی افسوس ناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عالمی امن کے قیام میں لیگ آف نیشنز کی ناکامی کے بعد اقوام متحدہ کا قیام اس مقصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ دنیا بھر کی اقوام کے درمیان انصاف اور مساوات کا اہتمام کر کے جارحیت کے ارتکاب کو روکا جائے اور عالمی امن کو تحفظ فراہم کیا جائے لیکن اقوام متحدہ اپنے نصف صدی کے کردار کے حوالے سے لیگ آف نیشنز سے بھی زیادہ ناکام ادارہ ثابت ہوا ہے اور وہ دنیا پر جارحانہ قبضے کے خواہش مند امریکی کیمپ کے ذیلی ادارے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور اس نے مظلوم اقوام کے خلاف جارحیت کا راستہ روکنے کے بجائے حملہ آور ملکوں کو جارحیت کے ارتکاب کے لیے این او سی جاری کرنے کا کاروبار سنبھال لیا ہے اس لیے اس ادارے کے باقی رہنے کا کوئی جواز موجود نہیں رہا اور اسے ختم کر کے اس کی جگہ موجودہ عالمی صورت حال اور معروضی حقائق کی بنیاد پر اقوام عالم کے درمیان ایک نئے معاہدے اور ایک نئے عالمی فورم کی تشکیل ناگزیر ہو گئی ہے جس کی بنیاد کسی ایک گروہ کی اجارہ داری اور اس کے مفادات کی بالادستی کے بجائے دنیا کی تمام اقوام کے درمیان انصاف کے قیام اور تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کے یکساں احترام وتحفظ پر ہو کیونکہ اس کے بغیر دنیا کو اس عالم گیر تباہی سے نہیں بچایا جا سکتا جسے نسل انسانی پر مسلط کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی چھتری تلے امریکی کیمپ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔
اعلامیہ میں جی ایٹ (G8) کی طرف سے عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کے پروگرام کو عالمی نوآبادیات کا ایک نیا ایڈیشن قرار دیا گیا جس کا مقصد پوری دنیا کے وسائل اور ذخائر پر آٹھ ملکوں کے قبضہ اور کنٹرول کی راہ ہموار کرنا ہے اور غریب اقوام وممالک کو غلامی کے ایک نئے شکنجے میں جکڑنا ہے ا س لیے اس کے خلاف دنیا کی مظلوم اقوام کو متحدہو جانا چاہیے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ بات بھی محض فریب ہے کہ عالمگیریت اور بین الاقوامیت کا آغاز اب کیا جا رہا ہے اور مغربی ممالک اس کا آغاز کر رہے ہیں اس لیے کہ انسانی معاشرے کو رنگ ونسل اور علاقہ اور دیگر محدود امتیازات سے نجات دلاتے ہوئے پوری نسل انسانی کے لیے ایک دین، ایک فلسفہ اور ایک نظام حیات کا اعلان اب سے ڈیڑھ ہزار سال قبل خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اور وہی انسانی سوسائٹی میں عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کا نقطہ آغاز تھا جس کے بعد صدیوں تک دنیا کی مختلف اقوام اور ممالک نے خلافت کے تحت ایک نظام اور فلسفہ کے مطابق باہمی احترام کے ساتھ زندگی بسر کی ہے لیکن مغرب صرف طاقت اور پراپیگنڈے کے زور پر اسلام کے اس اعزاز اور کریڈٹ کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے جس کا عالم اسلام کے علمی وفکری حلقوں کو سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔
اعلامیہ میں کہا گیا کہ امریکی کیمپ نے اپنے سیاسی، تہذیبی اور معاشی مقاصد کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے ایک نئی عالمگیر جنگ شروع کر دی ہے اور اقوام متحدہ نے اسے این او سی بھی جاری کر دیا ہے لیکن دہشت گردی کا کوئی متعین مفہوم طے کرنے کے بجائے اسے مبہم چھوڑ دیا گیا ہے جو ایک خطرناک سازش ہے جس کے ذریعے سے دہشت گردی اور تحریکات آزادی کو آپس میں خلط ملط کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی کسی بھی تحریک اور جدوجہد کو دہشت گرد قرار دینے کا اختیار حملہ آور مغربی قوتوں کے اپنے ہاتھ میں رہے اور وہ دنیا کے جس گروہ اور تحریک کو چاہیں، دہشت گرد قرار دے کر اسے جارحیت کا نشانہ بنا ڈالیں۔ اس سے دنیا بھر کی تحریکات آزادی کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے اور مظلوم اقوام وممالک کی آزادی اورخود مختاری سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ دہشت گردی کی واضح تعریف کی جائے اور دہشت گردی اور جہاد وآزادی کے درمیان فرق متعین کیا جائے ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ امریکی کیمپ آزادی کی تحریکات کو دہشت گردی کا نام دے کر جارحیت کا نشانہ بنانا چاہتا ہے اور ظالم وغاصب قوموں کے جبر واستحصال میں ان کا کھلم کھلا سرپرست ومعاون بن گیا ہے۔
اعلامیہ میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ نے فلسطین، کشمیر، چیچنیا اور عراق اور افغانستان وغیرہ میں نہتے شہریوں کے قتل عام اور ان پر ظالم وغاصب قوتوں کی وحشیانہ جارحیت پر جو مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور اقتصادی ناکہ بندی اور بمباری کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کے قتل اور عورتوں اور بچوں کی ہلاکت پر جس طرح آنکھیں بند کر لی ہیں، اس کے بعد انصاف ، امن اور داد رسی کے حوالے سے اقوام متحدہ سے کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ سینٹ اور کانگریس کی طرح اقوام متحدہ بھی امریکہ ہی کا کوئی ادارہ ہے جو دنیا بھر میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت اور بالادستی کی راہ ہموار کرنے کے لیے مصروف کار ہے۔
اعلامیہ میں مسلم سربراہ کانفرنس کی تنظیم کے کردار کو انتہائی افسوس ناک قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ دو تین کو چھوڑ کر باقی تمام مسلم حکمران ملت اسلامیہ اور اپنے ملکوں کے عوام کی نمائندگی کرنے کے بجائے امریکی کیمپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مغربی ملکوں کو عالم اسلام اور اپنے ملکوں کے جذبات واحساسات سے باخبر کرنے اور ان کے احترام پر آمادہ کرنے کے بجائے مغربی حکمرانوں کے خواہشات اور ایجنڈے کے مطابق اپنے عوام بالخصوص دینی حلقوں کو دبانے اور ریاستی جبر کا نشانہ بنانے میں مصروف ہے اور مسلم سربراہ کانفرنس کی تنظیم کو بھی انہوں نے اقوام متحدہ کی طرح بالادست اور جارح قوتوں کے مفادات کا محافظ بنا دیا ہے۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اسلامی سربراہ کانفرنس کی افادیت کا ازسرنو جائزہ لیا جائے اور مسلم سربراہوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر کے اس میں دوٹوک فیصلہ کیا جائے اور اگر یہ ادارہ عالم اسلام کے مفادات اورمسلمانوں کی مشکلات میں کوئی موثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اسے فوری طور پر ختم کر کے ملت اسلامیہ کو اس سنگین مذاق سے نجات دلائی جائے۔
ورلڈ اسلامک فورم کی مرکزی کونسل نے اپنے سالانہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ اعلامیہ میں مذکور مقاصد کے حصول اور اس کے لیے عالم اسلام کے دینی، سیاسی اور علمی حلقوں کو آمادہ کرنے کی غرض سے مہم چلائی جائے گی جس کے لیے ایک سال کا شیڈول طے کیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے مولانا محمد عیسیٰ منصوری، مولانا مفتی برکت اللہ ، مولانا رضاء الحق سیاکھوی، مولانامحمد اکرم ندوی اور جناب طٰہٰ قریشی پر مشتمل پانچ رکنی ورکنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔
اجلاس میں مغربی ممالک میں مقیم مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے موقف اور جذبات کو دلیل اور منطق کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں اور اپنے اپنے ملکوں کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے جذبات اور موقف کے اظہار کے لیے تمام قانونی ذرائع اختیار کریں نیز اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت وامداد کے لیے قانون کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، اس سے گریز نہ کریں۔ میڈیا تک رسائی کی کوشش کی جائے ۔ ہر علاقہ کے مسلمان دینی وسیاسی رہنما ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کریں۔ دینی وسیاسی رہنماؤں سے روابط استوار کریں۔ جنگ کے مخالف عناصر کی آواز کو تقویت پہنچائیں۔ مشترکہ اجتماعات کا اہتمام کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ افغانستان اور دیگر مسلم ممالک کے بے گھر افراد اور خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کریں۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یک طرفہ طور پر پھیلائے جانے والے شکوک وشبہات کے ازالہ کے لیے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم اسلام کی بہتری اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔
قافلہ میعاد
ادارہ
- برصغیر پاک وہند کے معروف عالم دین اور محدث حضرت مولانا عاشق الٰہی بلند شہری گزشتہ دنوں مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ حدیث نبوی کی تدریس میں بسر کیا اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ کچھ عرصہ قبل ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے اور اپنے مخصوص ذوق کے مطابق مسلمانوں کی علمی ودینی راہ نمائی میں مصروف تھے۔
- مانسہرہ ہزارہ کے سرگرم اور مجاہد عالم دین مولانا سید منظور احدم شاہ آسی گزشتہ دنوں انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ مدرسہ نصرۃ العلوم کے فاضل اور مدیر الشریعہ کے قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے مانسہرہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیۃ علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر مختلف دینی تحریکات میں سرگرم کردار ادا کیا اور مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی قدس اللہ سرہ العزیز کی سوانح وخدمات پر دو جلدوں میں ایک ضخیم کتاب بھی لکھی۔
- عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر حضرت مولانا سید نفیس الحسینی مدظلہ کے فرزند حافظ سید انیس الحسن شاہ زیدی گزشتہ دنوں انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم ایک اچھے خوش نویس تھے اور حضرت شاہ صاحب مدظلہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔
- مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے پرانے استاذ مولانا سید عطاء اللہ شاہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کے پھوپھی زاد بھائی مولانا سید فتح علی شاہ مرحوم آف لمی (بٹل ہزارہ) کے فرزند تھے ۔ مدرسہ نصرۃ العلوم کے فاضل تھے اور مدرسہ کے سکول میں ایک عرصہ سے تدریسی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔
- کامونکی گوجرانوالہ کے معروف خوش نویس اور دینی کارکن حافظ محمد شوکت گزشتہ روز حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم مجلس تحفظ ختم نبوت گوجرانوالہ کے دفتر میں بیٹھتے تھے اور دینی تحریکات میں سرگرم حصہ لیتے تھے۔
ہم دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب مرحومین کی حسنات قبول فرمائیں، سیئات سے درگزر کریں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں۔ نیز پس ماندگان کو صبرجمیل کی توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’سیرت سلطان ٹیپو شہیدؒ‘‘
سلطان فتح علی ٹیپو شہیدؒ اور ان کے والد محترم سلطان حیدر علیؒ جنوبی ایشیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرنگی استعمار کے تسلط کے خلاف مسلمانوں کی شاندار تحریک مزاحمت کا وہ روشن کردار ہیں جنہوں نے اس دور میں جنوبی ہند میں ایک اسلامی ریاست ’’سلطنت خداداد میسور‘‘ کے نام سے قائم کی اور فرنگی استعمار کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک کر اس خطہ کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ اگر وہ جذبہ ایمانی کے اظہار کے لیے متحد ہو جائیں تو اپنے وطن کی آزادی اور دینی تشخص کو استعماری حملہ آوروں کی یلغار سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے لیکن یہ مردمجاہد ۴ مئی ۱۷۹۹ء کو اپنوں کی غداری کے باعث سرنگا پٹم کے محاذ پر انگریزی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا اور اس کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں قائم ہونے والی یہ اسلامی ریاست بھی ختم ہو گئی۔ سلطان ٹیپوؒ کی شہادت پر انگریزی فوج کے کمانڈر جنرل ہارس نے شہید کی لاش پرکھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ ’’آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔‘‘ اور فی الواقع اس کے بعد مسلمانوں کے قدم جنوبی ایشیا میں کسی جگہ بھی انگریزی فوجوں کے آگے جم نہ سکے۔ سلطان ٹیپو شہیدؒ کے حالات زندگی اور خدمات پر یہ کتاب مفکراسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ کی خواہش پر اور ان کی نگرانی میں مولانا محمد الیاس ندوی نے لکھی ہے جس میں سلطان حیدر علیؒ اور سلطان ٹیپوؒ کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ’’سلطنت خداداد میسور‘‘ کے قیام اور پھر سقوط کے اسباب پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور ہمار ے خیال میں امارت اسلامی افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ پیش آنے والے حالیہ واقعات کے پس منظر میں دینی کارکنوں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ کتاب مجلس تحقیقات اسلام ونشریات اسلام لکھنو نے شائع کی ہے اور چھ سو کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل اس مجلد کتاب کی قیمت ۱۰۰ روپے ہے۔
’’واردات و مشاہدات‘‘
ماہنامہ ’’الرشید‘‘ لاہور کے مدیر مولانا حافظ عبد الرشید ارشد کو قدرت نے واقعہ نگاری اور تذکرہ نویسی کا خصوصی ذوق عطا فرمایا ہے اور انہوں نے اسے اہل حق کے قافلہ علماء دیوبند کی خدمات وحالات کے لیے وقف کر کے اہل حق کی جدوجہد اور تگ وتاز کے اہم شواہد ومناظر کو تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔ ’’بیس بڑے مسلمان‘‘ اور ’’بیس مردان حق‘‘ کے علاوہ ’’الرشید‘‘ کی متعدد خصوصی اشاعتوں کے ذریعے سے اس شعبہ میں جو کام انہوں نے تنہا سرانجام دیا ہے، وہ قابل رشک ہے اور اس پر ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔
انہوں نے مختلف اوقات میں ’’الرشید‘‘ میں شخصیات کے حوالے سے جو شذرات لکھے ہیں اور متعدد واقعات کے بارے میں اپنے مشاہدات وتاثرات کو وقتاً فوقتاً قلم بند کیا ہے، وہ اس دور کی دینی شخصیات اور تحریکات پر معلومات کا ایک خزانہ ہے جسے انہوں نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت یکجا کر کے استفادہ کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔
آٹھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل یہ خوب صورت اور مجلد کتاب حافظ صاحب موصوف کے مخصوص ذوق طباعت کی آئینہ دار ہے جس کی قیمت تین سو روپے ہے اور اسے مکتبہ رشیدیہ، ۲۵ لوئر مال، لاہور سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
’’مغربی میڈیا اور اس کے اثرات‘‘
دنیا بھر کے مسلمانوں کو شکایت ہے کہ مغربی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ پیش کر رہا ہے، وہ صحیح تصویر نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کی مخصوص معاندانہ ذہنیت کی آئینہ دار ہے۔ مولانا نذر الحفیظ ندوی نے اسی شکایت کا محققانہ جائزہ لیا ہے اور مغربی میڈیا کے اہداف ومقاصد اور طریق کار کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر رونما ہونے والے اس کے اثرات کا تفصیلی نقشہ پیش کیا ہے۔ ہمارے خیال میں دینی جماعتوں کے راہ نماؤں اور کارکنوں بالخصوص ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے حضرات کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے تاکہ وہ یہ بات صحیح طور پر سمجھ سکیں کہ مغربی میڈیا کون سا کام کر رہا ہے اور کس انداز سے کر رہا ہے تاکہ وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور طریق کار کا ازسرنو جائزہ لے سکیں۔ یہ کتاب دار العلوم ندوۃ العلما لکھنو نے شائع کی ہے۔ اس کے صفحات چار سو سے زائد ہیں اور قیمت نوے روپے درج ہے۔
’’انسانی حقوق‘‘
جمعیۃ علماء اسلام صوبہ سرحد کے فاضل دانش ور مولانا محمد رحیم حقانی نے انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کی حالیہ مہم کے پس منظر میں جمعیۃ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے بعض معلومات خطابات کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بہت سی ضروری معلومات کو یکجا کر دیا ہے اور موجودہ حالات میں ایک اہم ضرورت کو ایک حد تک پورا کر دیا ہے۔
۱۳۶ صفحات کی اس مجلد کتاب کی قیمت ۵۰روپے ہے اور جمعیۃ پبلی کیشنز جامع مسجد پائلٹ سکول وحدت روڈ لاہور نے اسے شائع کیا ہے۔
مئی و جون ۲۰۰۱ء
اہلِ علم سے ایک گزارش
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
رمضان المبارک کے بعد ملک کے معروف دانشور جناب جاوید احمد غامدی اور ان کے تلامذہ کے ساتھ بعض علمی و دینی مسائل پر گفتگو کا سلسلہ چل نکلا تھا اور اس سلسلے میں دونوں طرف سے مضامین مختلف اخبارات و جرائد مثلاً روزنامہ جنگ، روزنامہ اوصاف، روزنامہ پاکستان، ماہنامہ اشراق اور ماہنامہ تجلیاتِ حبیب چکوال میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان مضامین کو الشریعہ کی زیرنظر اشاعت میں اہلِ علم کی خدمت میں یکجا پیش کیا جا رہا ہے۔ اربابِ علم و دانش سے گزارش ہے کہ وہ ان مضامین کا توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں اور اگر کسی حوالے سے اپنی رائے کے اظہار کی ضرورت محسوس کریں تو اس سے ہمیں بلاتامل آگاہ فرمائیں۔ ہمارے خیال میں اس قسم کے مسائل پر آزادانہ علمی مباحثہ ضروری ہے کیونکہ اسی سے فکری الجھنوں کی گرہیں کھلتی ہیں اور اہلِ علم کے لیے کسی معاملے میں رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
امید ہے کہ یہ معمولی سی کاوش اربابِ علم و دانش کی توجہات اور حوصلہ افزائی سے محروم نہیں رہے گی۔ ضخامت میں اضافہ کے باعث زیرنظر شمارہ مئی اور جون ۲۰۰۱ء کا مشترکہ شمارہ ہو گا اور اگلا شمارہ جولائی کے آغاز میں قارئین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔
گزشتہ دنوں ملک کی دو نامور دینی شخصیات (۱) جمعیۃ علماء پاکستان کے سربراہ مولانا عبد الستار خان نیازی اور (۲) جمعیۃ اہلِ حدیث پاکستان کے سرپرست مولانا محمد عبد اللہ دارفانی سے رحلت کر گئے۔ ملک میں دینی اقدار کے تحفظ و فروغ کے لیے دونوں حضرات کی خدمات لائقِ تحسین رہی ہیں۔ ان کے علاوہ حافظ آباد کے بزرگ عالم دین مولانا حکیم نور احمد یزدانی کا انتقال ہو گیا ہے جو جمعیۃ علماء اسلام کے ابتدائی راہنماؤں میں سے تھے۔ علاوہ ازیں گکھڑ کے معروف ادیب و دانش جناب شمس کاشمیری کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک دیندار گھرانے کے دیندار فرد اور متعدد ادبی کتابوں کے مصنف تھے، کچھ عرصہ تک ایبٹ آباد سے ہزارہ ٹائمز کے نام سے ایک جریدہ بھی شائع کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے مولانا مفتی محمد اقبال کی والدہ محترمہ بھی رحلت فرما گئی ہیں۔
ہم ان سب مرحومین کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں جوارِ رحمت میں جگہ دیں اور پسماندگان کو صبرِ جمیل کی توفیق سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔
حدیثِ رسولؐ پڑھنے اور پڑھانے کے آداب
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
جس مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہو اس مجلس میں شوروغل برپا کرنا سخت بے ادبی ہے کیونکہ آپ کے ارشاد کا احترام بعد از وفات بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ آپ کی حیات میں تھا۔
جلیل القدر محدث اور حضرت امام بخاریؒ کے استاد امام عبد الرحمٰن بن مہدیؒ (المتوفٰی ۱۹۸ھ) کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے سامنے حدیث پڑھی یا سنائی جاتی تو وہ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے: ’’لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی‘‘ کہ اپنی آوازوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ نیز فرماتے تھے کہ حدیث پڑھتے پڑھاتے وقت خاموش رہنا اسی طرح لازم ہے جس طرح آپ کے دنیا میں ارشاد فرمانے کے وقت لازم تھا۔ (مدارج النبوۃ ج ۱ ص ۵۲۹)
حافظ ابن القیمؒ (المتوفٰی ۷۵۱ھ) فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا جب موجبِ حبطِ اعمال ہے تو آپ کی سنت اور احکام کے مقابلے میں اپنی رائے، رسم و رواج اور بدعات پر عمل کرنا کیونکر اعمالِ صالحہ کے لیے تباہ کن نہ ہو گا۔ (اعلام الموقعین ج ۱ص ۴۲)
رئیس التابعین حضرت سعید بن المسیبؒ (المتوفٰی ۹۳ھ) ایک پہلو پر (بیمار ہونے کی وجہ سے) لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے ان سے ایک حدیث دریافت کی۔ وہ فورًا اٹھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی۔ سائل نے کہا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بیان کروں۔ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۱۹ ۔ مدارج النبوۃ ج ۱ ص ۵۴۱)
حضرت امام مالکؒ (المتوفٰی ۱۷۹ھ) کا یہ معمول تھا کہ جب حدیث بیان فرماتے تو پہلے غسل کرتے، پھر خوشبو لگاتے اور عمدہ لباس پہن کر نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ حدیث بیان کرتے اور آخر دم تک اسی حالت میں رہتے (مدارج النبوۃ ج ۱ ص ۵۴۲)۔ امام صاحبؒ حدیث کی تعظیم کے پیشِ نظر باوضو ہی حدیثیں بیان کرتے تھے (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۹۹)۔
قرآنِ کریم اور عربی زبان
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
قرآنِ مجید میں ارشاد ہے کہ اس قرآن کو روح الامین لے کر آئے ہیں ’’بلسانٍ عربی مبین‘‘ (الشعراء ۱۹۵) جس کی زبان عربی ہے جو کہ بالکل واضح اور فصیح زبان ہے۔ اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ عربی زبان میں نازل ہونے والا یہ قرآن پاک اپنے مضامین، مطالب، معانی، دلائل، مسائل، احکام و شواہد کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کہلانے کا مستحق وہی نسخہ ہو گا جو عربی زبان میں ہو گا، کسی دوسری زبان میں ہونے والا ’’ترجمۂ قرآن‘‘ تو کہلا سکتا ہے لیکن قرآن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ’’فاقرءوا ما تیسر من القرآن‘‘ (المزمل ۲۰) یعنی نماز میں جتنی سہولت ہو قرآن پڑھا کرو۔ اور قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی۔
بعض ملحد قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عربی کو سمجھتے نہیں لہٰذا اگر نماز اپنی زبان اردو پنجابی وغیرہ میں پڑھ لیا کریں تو مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور نماز اچھے طریقے سے ادا ہو گی۔ یہ سخت بے دینی کی بات ہے۔ بجائے اس کے کہ نماز اور قرآن پاک کی چند سورتوں کا ترجمہ سیکھ لیا جائے، انہوں نے نماز کو اردو میں منتقل کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انگریزی، فارسی، فرانسیسی اور جرمن زبانیں سیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے مگر قرآن پاک کی زبان عربی کی باری آتی ہے تو اس کو سیکھنے کے بجائے قرآن اور نماز کے ترجمے پر گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی تھوڑی سی کوشش کر کے نماز کی حد تک تو قرآن کے الفاظ اور ترجمہ سیکھ لیتا ہے اور پھر پوری دلجمعی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔
دینی مدارس اور موجودہ حکومت
ڈاکٹر محمد امجد تھانوی
ماضی میں کئی حکومتوں نے دینی مدارس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوششیں کیں لیکن وہ اس میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکیں کہ پاکستان کے دینی حلقوں نے ان کی اس کوشش پر شدید تنقید کر کے اپنے ردعمل کا اظہار کیا۔ اسی طرح اب موجودہ حکومت امریکی مطالبے پر اور این جی اوز کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ملک میں دینی مدارس کے خلاف اور جہادی تحریکوں کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔
اس سلسلے میں کابینہ کے ارکان اور بارہ علماء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا مقصد مدارس کے طریقۂ تعلیم میں تبدیلی لانا ہے جو کہ ایک طویل عرصے سے درسِ نظامی کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چند امریکی سینیٹروں نے پاکستان کی حکومت کے اعلیٰ حکام سے جب ملاقات کی تو انہوں نے دینی مدارس اور مساجد کا ذکر بھی کیا اور اس سلسلے میں انتہاپسندی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خوف کا اظہار کیا، لیکن حکومت کے ایک معزز عہدیدار نے
- انہیں یقین دہانی کرائی کہ اسلام صبر، برداشت، رواداری، تحمل اور عالمگیر اقدار کی ترویج کا درس دیتا ہے اور ہمارے دینی مدارس ان کے امین ہیں۔
- اور یہ بھی کہا کہ مدارس اور مساجد ہمارے معاشرے اور ثقافت کا مرکز ہیں۔
- انہوں نے امریکی وفد کو یہ بھی بتایا کہ افغان جنگ کے دوران، جو روس اور افغانستان کے درمیان ہوئی، مجاہدین کافی مضبوط ہو چکے ہیں اور اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم ان کو سدھار دیں گے جس میں وقت لگے گا۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت دینی مدارس کے سلسلے میں اپنا لائحہ عمل بنائے گی اور اس سلسلے میں وفاقی وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی ملک کے اندر اپنے لائحہ عمل کے مطابق دارالعلوم قائم کریں جہاں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی۔ کیونکہ مدارس کو نہ تو ایک دم ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ حکومت فوری طور پر ان کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے۔ حکومت کی مقرر کردہ کمیٹی نے حکومت کو یہ یقین دلایا ہے کہ دینی مدارس کو ریگولرائز کرنے کا طریقہ کار طے کر لیا جائے گا۔
ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت امریکی خواہش کے مطابق اپنے فیصلوں کو دینی مدارس پر نافذ کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم مدارس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن دینی مدارس کو جدید ایجوکیشن سنٹر بنا کر ان کا نصاب تبدیل کر دیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کی روح کو سلب کر لیا جائے گا۔
حکومت نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ نصاب کی تبدیلی کا مقصد بے روزگاری، تنگ نظری، عصبیت اور جاہلیت پر قابو پانا ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے کبھی بے روزگار نہیں رہتے، کبھی حکومت سے ملازمتوں کی بھیک نہیں مانگتے، کبھی نوکریوں سے برطرف نہیں ہوتے، پھر اچانک موجودہ حکومت کو ان کی بے روزگاری کا خیال کیسے آیا؟
موجودہ حکومت اگر ملک کے کالجز اور یونیورسٹیوں کا جائزہ لے تو اس کو معلوم ہو گا کہ تنگ نظری، عصبیت، جاہلیت، ضد اور ہٹ دھرمی کے مراکز ملک کی مختلف جامعات، کالجز اور اسی قسم کے مغربی تعلیمی ادارے ہیں۔ جامعہ کراچی (کراچی یونیورسٹی) سمیت ملک کے تعلیمی اداروں میں طلبا کے جھگڑوں میں قتل ہونے والوں کی تعداد کئی سو سے زیادہ ہے۔ جبکہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی دینی مدرسے کے کسی طالب علم نے کبھی اپنے مدرسے میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس وقت جامعہ کراچی، این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور کراچی کے دوسرے کالجز میں خاص طور پر رینجرز اور فوج کے نوجوان پہرہ دے رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے کسی بھی دینی مدرسے میں تصادم کو روکنے کے لیے فوج، پولیس اور رینجرز کو نہیں بلایا جاتا۔
مغربی تعلیمی اداروں میں ہڑتالیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی بے عزتی کی جاتی ہے، حکومت کی گرانٹ کے باوجود ہنگاموں کے باعث جامعات اور کالجز بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان کے تمام دینی مدارس خواہ وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں مغربی تعلیمی اداروں سے ہزارہا درجے بہتر چل رہے ہیں۔
ایک جائزے کے مطابق پاکستان میں دینی مدارس میں طلبا و طالبات کی تعداد سات لاکھ سے زیادہ ہے جس میں تقریباً تین لاکھ طلبا ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اٹھانوے ہزار طلبا قرآن کریم کے حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چالیس ہزار طلبا تجوید قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ترپن ہزار طلبا قراءت سیکھ رہے ہیں، اور چھبیس ہزار سے زیادہ طلبا درس نظامی کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تقریباً اٹھاون ہزار طالبات بھی اس ملک میں دینی مدارس میں رائج نظام کے مطابق اپنی دینی تعلیمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی سو طلبا پورے ملک میں فتوے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں مہارت کے بعد وہ دین کے سلسلے میں مسلمانان پاکستان کی رہنمائی کرتے ہیں جس کو پاکستان کی عدالتِ عالیہ اور عدالتِ عظمٰی نے بھی تسلیم کیا ہے۔
ہم حکومت سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہ ہیں جن کی بنا پر وفاقی وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی نگرانی میں دینی مدارس میں نیا نصاب رائج کرنے اور مدارس کے کلچر کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیکولرازم، فاشزم اور مغربی یلغار کا مقابلہ صرف اور صرف دینی مدارس کر سکتے ہیں۔
غامدی صاحب کے ارشادات پر ایک نظر
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے محترم اور بزرگ دوست ہیں، صاحب علم ہیں، عربی ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں، وسیع المطالعہ دانشور ہیں، اور قرآن فہمی میں حضرت مولانا حمید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان دنوں قومی اخبارات میں غامدی صاحب اور ان کے شاگرد رشید جناب خورشید احمد ندیم کے بعض مضامین اور بیانات کے حوالے سے ان کے کچھ تفردات سامنے آرہے ہیں جن سے مختلف حلقوں میں الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ اور بعض دوستوں نے اس سلسلہ میں ہم سے اظہار رائے کے لیے رابطہ بھی کیا ہے۔ آج بھی ایک قومی اخبار کے لاہور ایڈیشن میں پشاور پریس کلب میں غامدی صاحب کے ایک خطاب کے حوالہ سے ان کے بعض ارشادات سامنے آئے ہیں اور انہی کے بارے میں ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ مگر پہلے غامدی صاحب کے علمی پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ ان کی بات صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ہی ہم اپنی بات وضاحت کے ساتھ کہہ پائیں گے۔
حضرت مولانا حمید الدین فراہیؒ برصغیر پاک و ہند کے سرکردہ علماء کرام میں سے تھے اور مولانا شبلی نعمانیؒ کے ماموں زاد تھے۔ ان کے اساتذہ میں مولانا شبلیؒ کے علاوہ مولانا عبد الحئی فرنگی محلیؒ، مولانا فیض الحسن سہارنپوریؒ اور پروفیسر آرنلڈ شامل ہیں۔ دینی درسیات کی تکمیل کے بعد انہوں نے جدید تعلیم بھی حاصل کی اور وہ بیک وقت عربی، اردو، فارسی، انگلش اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ حیدر آباد دکن کے دارالعلوم کے پرنسپل رہے جسے بعد میں جامعہ عثمانیہ کے نام سے یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کو ’’جامعہ‘‘ کی شکل دینے میں مولانا فراہیؒ کی سوچ اور تحریک بھی کار فرما تھی۔ بعد میں حیدرآباد کو چھوڑ کر انہوں نے لکھنو کے قریب سرائے میر میں مدرسۃ الاصلاح کے نام سے درسگاہ کی بنیاد رکھی اور قرآن فہمی کا ایک نیا حلقہ قائم کیا جو اپنے مخصوص ذوق اور اسلوب کے حوالہ سے انہی کے نام سے منسوب ہوگیا۔
جہاں تک میں سمجھتا ہوں مولانا فراہیؒ کے نزدیک قرآن فہمی میں عربی ادب، نزول قرآن کے دور کے عربی لٹریچر اور روایات، اور اس کے ساتھ تعرف و تعامل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ حدیث و سنت کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں مگر ’’خبر واحد‘‘ کو ان کے ہاں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو محدثین کے ہاں تسلیم شدہ ہے، اور وہ احکام میں خبر واحد کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے بعض علمی معاملات میں ان کی اور ان کے تلامذہ کی رائے جمہور علماء سے مختلف ہو جاتی ہے۔ مولانا فراہیؒ کے بعد ان کے فکر اور فلسفہ کے سب سے بڑے وارث اور نمائندہ حضرت مولانا امین احسن اصلاحیؒ تھے جنہوں نے کچھ عرصہ قبل وفاقی شرعی عدالت میں شادی شدہ مرد و عورت کے لیے زنا کی سزا کے طور پر ’’رجم‘‘ کی شرعی حد نہ ہونے پر دلائل فراہم کیے تھے اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ رجم اور سنگسار کرنا شرعی حد نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی خبر واحد کے احکام میں حجت نہ ہونے کا تصور کارفرما تھا۔
یہ ایک مستقل علمی بحث ہے کہ احکام و قوانین کی بنیاد شہادت پر ہے یا خبر پر۔ پھر خبر اور شہادت کے نصاب و معیار میں کیا فرق ہے۔ اس میں فقہاء کے اصولی گروہ میں سے بعض ذمہ دار بزرگ ایک مستقل موقف رکھتے ہیں، جبکہ جمہور محدثین اور عملی فقہاء کا موقف ان سے مختلف ہے۔ ہمارے خیال میں مولانا حمید الدین فراہیؒ کا موقف جمہور فقہاء اور محدثین کی بجائے بعض اصولی فقہاء سے زیادہ قریب ہے، اسی وجہ سے ہم اسے ان کے تفردات میں شمار کرتے ہیں۔ اور تفردات کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر صاحب علم کا حق ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے بشرطیکہ وہ ان کی ذات یا حلقہ تک محدود رہے۔ البتہ اگر کسی تفرد کو جمہور اہل علم کی رائے کے علی الرغم سوسائٹی پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ فکری انتشار اور ایک نئے مکتب فکر کے قیام کا سبب بنتا ہے۔ اور یہی وہ نکتہ اور مقام ہے جہاں ہمارے بہت سے قابل قدر اور لائق احترام مفکرین نے ٹھوکر کھائی ہے اور امت کے اجتماعی علمی دھارے سے کٹ کر جداگانہ فکری حلقوں کے قیام کا باعث بنے ہیں۔ بہرحال محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے شاگرد رشید خورشید احمد ندیم صاحب کا تعلق اسی علمی حلقہ سے ہے اور مولانا امین احسن اصلاحیؒ کے بعد اس حلقہ علم و فکر کی قیادت غامدی صاحب فرما رہے ہیں۔
پس منظر کی وضاحت کے طور پر ان تمہیدی گزارشات کے بعد ہم غامدی صاحب محترم کے ان ارشادات کی طرف آرہے ہیں جو انہوں نے گزشتہ روز پشاور پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے فرمائے ہیں اور جنہیں مذکورہ اخبار نے اس طرح رپورٹ کیا ہے کہ:
- علماء کرام خود سیاسی فریق بننے کی بجائے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی اصلاح کریں تو بہتر ہوگا، مولوی کو سیاستدان بنانے کی بجائے سیاست دان کو مولوی بنانے کی کوشش کی جائے۔
- زکوٰۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹیکسیشن کو ممنوع قرار دے کر حکمرانوں سے ظلم کا ہتھیار چھین لیا ہے۔
- جہاد تبھی جہاد ہوتا ہے جب مسلمانوں کی حکومت اس کا اعلان کرے، مختلف مذہبی گروہوں اور جتھوں کے جہاد کو جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔
- فتوؤں کا بعض اوقات انتہائی غلط استعمال کیا جاتا ہے اس لیے فتویٰ بازی کو اسلام کی روشنی میں ریاستی قوانین کے تابع بنانا چاہیے اور مولویوں کے فتوؤں کے خلاف بنگلہ دیش میں فیصلہ صدی کا بہترین عدالتی فیصلہ ہے۔
جہاں تک پہلی بات علماء اور سیاست کا تعلق ہے کہ علماء کرام خود سیاسی فریق بننے کی بجائے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی اصلاح کریں تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ موقع محل اور حالات کی مناسبت کی بات ہے اور دونوں طرف اہل علم اور اہل دین کا اسوہ موجود ہے۔ امت میں اکابر اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے حکمرانوں کے خلاف سیاسی فریق بننے کی بجائے ان کی اصلاح اور راہ نمائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن ایسے اہل علم بھی امت میں رہے ہیں جنہوں نے اصلاح کے دوسرے طریقوں کو کامیاب نہ ہوتا دیکھ کر خود فریق بننے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی مثال حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ ہیں جن کا شمار صغار صحابہؓ میں ہوتا ہے اور وہ بنیادی طور پر اہل علم میں سے تھے۔ لیکن حضرت معاویہؓ کے بعد انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار بلکہ اس کے خلاف فریق بن گئے اور متوازی حکمران کے طور پر کئی برس تک حجاز اور دوسرے علاقوں پر حکومت کرتے رہے۔ اس لیے اگر کسی دور میں علماء کرام یہ سمجھیں کہ خود فریق بنے بغیر معاملات کی درستگی کا امکان کم ہے تو اس کا راستہ بھی موجود ہے اور اس کی مطلقاً نفی کر دینا دین کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔
زکوٰۃ کے بارے میں غامدی صاحب کا ارشاد گرامی ہم سمجھ نہیں پائے۔ اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو مکمل طور پر اپنانے کی صورت میں اسلامی حکومت کو کسی اور ٹیکس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی تو یہ بات سو فیصد درست ہے۔ اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست قرآن و سنت کی بنیاد پر زکوٰۃ و عشر کے نظام کو من و عن اپنا لے اور اس کو دیانتداری کے ساتھ چلایا جائے تو اسے اور کوئی ٹیکس لوگوں پر لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور ملک بہت جلد ایک خوشحال رفاہی سلطنت کی شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن کیا کسی ضرورت کے موقع پر اس کے علاوہ کوئی ٹیکس لگانے کی شرعاً ممانعت ہے؟ اس میں ہمیں اشکال ہے۔ اگر غامدی صاحب محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کے بعد کسی اور ٹیکسیشن کی ممانعت پر کوئی دلیل پیش فرما دیں تو ان کی مہربانی ہوگی اور اس باب میں ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدانخواستہ ہم ٹیکسیشن کے موجودہ نظام کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ نظام تو سراسر ظالمانہ ہے اور شریعت اسلامیہ کسی پہلو سے بھی اس کی روادار نہیں ہے۔ مگر اسلامی نظام میں زکوٰۃ کے نظام کے بعد کسی اور ٹیکسیشن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے اور اسی کے لیے ہم غامدی صاحب سے علمی راہ نمائی کے طلب گار ہیں۔
محترم جاوید احمد غامدی صاحب کو مختلف جہادی گروپوں کی طرف سے جہاد کے نام پر مسلح سرگرمیوں پر اشکال ہے اور وہ ان کے اس عمل کو جہاد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ جہاد کا اعلان صرف ایک مسلم حکومت ہی کر سکتی ہے اس کے سوا کسی اور کو جہاد کا اعلان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مگر ہمیں ان کے اس ارشاد سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کی مختلف عملی صورتیں اور درجات ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ملک یا قوم کے خلاف جہاد کا اعلان اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک اسلامی یا کم از کم مسلمان حکومت اس کا اعلان کرے۔ لیکن جب کسی مسلم آبادی پر کفار کی یلغار ہو جائے اور کفار کے غلبہ کی وجہ سے مسلمان حکومت کا وجود ختم ہو جائے یا وہ بالکل بے بس دکھائی دینے لگے تو غاصب اور حملہ آور قوت کے خلاف جہاد کے اعلان کے لیے پہلے حکومت کا قیام ضروری نہیں ہوگا اور نہ ہی عملاً ایسا ممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسے مرحلہ میں مسلمانوں کی اپنی حکومت کا قیام قابل عمل ہو تو کافروں کی یلغار اور تسلط ہی بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ صورت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں کی حکومت کفار کے غلبہ اور تسلط کی وجہ سے ختم ہو جائے، بے بس ہو جائے، یا اسی کافر قوت کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن کر رہ جائے۔
سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ اگر جاوید غامدی صاحب محترم کا فلسفہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ ضروری ہوگا کہ مسلمان پہلے اپنی حکومت قائم کریں اور اس کے بعد اس حکومت کے اعلان پر جہاد شروع کیا جائے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوگا کہ جب مسلمانوں نے اپنی حکومت بحال کر لی ہے تو اب جہاد کے اعلان کی ضرورت ہی کیا باقی رہ گئی ہے؟ کیونکہ جہاد کا مقصد تو کافروں کا تسلط ختم کر کے مسلمانوں کا اقتدار بحال کرنا ہے اور جب وہ کام جہاد کے بغیر ہی ہوگیا ہے تو جہاد کے اعلان کا کون سا جواز باقی رہ جاتا ہے؟
اس کی ایک عملی مثال سامنے رکھ لیجیے کہ فلسطینی عوام نے تنظیم آزادی فلسطین کے عنوان سے غیر سرکاری سطح پر اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ سالہا سال کی مسلح جدوجہد کے نتیجہ میں مذاکرات کی نوبت آئی اور ان مذاکرات کے بعد ایک ڈھیلی ڈھالی یا لولی لنگڑی حکومت جناب یاسر عرفات کی سربراہی میں قائم ہوئی جو اس وقت بین الاقوامی فورم پر فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اگر مسلح جدوجہد نہ ہوتی تو مذاکرات اور حکومت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسلح جدوجہد کسی حکومت کے اعلان پر نہیں بلکہ غیر سرکاری فورم کی طرف سے شروع ہوئی اور اسی عنوان سے مذاکرات کی میز بچھنے تک جاری رہی۔ یہاں عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مسلح جدوجہد کے نتیجہ میں قائم ہوئی ہے نہ کہ حکومت نے قائم ہونے کے بعد مسلح جدوجہد یا جہاد کا اعلان کیا۔ لیکن اگر غامدی صاحب کے فلسفہ کو قبول کر لیا جائے تو یہ ساری جدوجہد غلط قرار پاتی ہے۔ اور ان کے خیال میں فلسطینیوں کو یہ چاہیے تھا یا شرعاً ان کے لیے جائز راستہ یہ تھا کہ وہ پہلے ایک حکومت قائم کرتے اور پھر وہ حکومت جہاد کا اعلان کرتی، تب ان کی مسلح جدوجہد غامدی صاحب کے نزدیک شرعی جہاد قرار پا سکتی تھی۔
خود ہمارے ہاں برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے بعد مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی نے کٹھ پتلی کی حیثیت اختیار کر لی اور عملاً انگریزوں کا اقتدار قائم ہوگیا تو اس وقت کے علماء کے سرخیل حضرت شاہ عبد العزیز دہلویؒ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور پھر بالا کوٹ کے معرکے تک اور اس کے بعد ۱۸۵۷ء میں مسلح جہاد آزادی کے مختلف مراحل تاریخ کا حصہ بنے۔ جہاد کا یہ اعلان بھی غیر سرکاری فورم کی طرف سے تھا اور شاہ عبد العزیز دہلویؒ یا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے دیگر علماء کو کوئی سرکاری اتھارٹی حاصل نہیں تھی۔ اس لیے غامدی صاحب کے فلسفہ کی رو سے یہ سارا عمل غیر شرعی قرار پاتا ہے۔ محترم غامدی صاحب یا ان کا کوئی شاگرد رشید اس دور میں موجود ہوتا تو وہ شاہ عبد العزیز دہلویؒ کو یہی مشورہ دیتا کہ حضور! آپ کو جہاد کے اعلان کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی حکومتی معاملات میں فریق بننے کا آپ کے لیے کوئی جواز ہے۔ آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ حکومت کی راہ نمائی کریں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آلۂ کار کی حیثیت اختیار کر جانے والے مغل بادشاہ کو مشورہ دیتے رہیں اور اس سے کہیں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، کیونکہ اس کے سوا جہاد کا اعلان کرنے کا شرعی اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے۔
جہاد افغانستان کی صورتحال بھی کم و بیش اسی طرح کی ہے کہ جب کابل میں روسی فوجیں اتریں، مسلح غاصبانہ قبضہ کے بعد افغانستان کے معاملات پر روس کا کنٹرول قائم ہوگیا اور ببرک کارمل کی صورت میں ایک کٹھ پتلی حکمران کو کابل میں بٹھا دیا گیا تو افغانستان کے مختلف حصوں میں علماء کرام نے اس تسلط کو مسترد کرتے ہوئے حملہ آور قوت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ بعد میں ان کے باہمی روابط قائم ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ چند گروپوں کی صورت میں یکجا ہوگئے۔ پھر انہیں روسی فوجوں کے خلاف مسلح جدوجہد میں ثابت قدم دیکھ کر باہر کی قوتیں متوجہ ہوئیں اور روس کی شکست کی خواہاں قوتوں نے ان مجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجہ میں روس کو افغانستان سے نکلنا پڑا اور سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہوگیا۔ غامدی صاحب کے اس ارشاد کی رو سے یہ سارا عمل غیر شرعی اور ناجائز ٹھہرتا ہے اور ان کے خیال میں افغان علماء کو از خود جہاد کا اعلان کرنے کی بجائے ببرک کارمل کی رہنمائی کرنے تک محدود رہنا چاہیے تھا، اور اس سے درخواست کرنی چاہیے تھی کہ چونکہ شرعاً جہاد کے اعلان کا اختیار صرف اس کے پاس ہے اس لیے وہ روسی حملہ آوروں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، تاکہ اس کی قیادت میں علماء کرام جہاد میں حصہ لے سکیں۔
فرانسیسی استعمار کے تسلط کے خلاف الجزائر کے علماء کو بھی اسی قسم کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہاں کے قوم پرست لیڈروں بن باللہ، بومدین اور بو نسیاف کے ساتھ ساتھ الشیخ عبد الحمید بن بادیسؒ اور الشیخ بشیر الابراہیمیؒ جیسے اکابر علماء نے بھی مسلح جدوجہد کی قیادت کی۔ انہوں نے فرانسیسی استعمار کے خلاف مسلح جدوجہد کو جہاد قرار دیا، اس کے لیے علماء کی باقاعدہ جماعت بنائی، اور جمعیۃ علماء الجزائر کے پلیٹ فارم سے سالہا سال تک غاصب حکومت کے خلاف مسلح جنگ لڑ کر الجزائر کی آزادی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بلکہ الشیخ عبد الحمید بن بادیسؒ کو یہ مشورہ ہی ان کے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمدؒ مدنی نے دیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مولانا مدنیؒ ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور مسجد نبوی میں حدیث نبویؐ پڑھایا کرتے تھے۔ الشیخ عبد الحمید بن بادیسؒ نے ان سے حدیث پڑھی اور وہیں مدینہ منورہ میں کسی جگہ بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرنے کی اجازت طلب کی تو شیخ مدنیؒ نے ان سے کہا کہ ان کا ملک غلام ہے اس لیے وہ واپس جائیں اور علماء کرام کو منظم کر کے اپنے وطن کی آزادی کے لیے جہاد کریں۔ اگر اس وقت شیخ بن بادیسؒ کے ذہن میں کوئی ’’دانشور‘‘ یہ بات ڈال دیتا کہ آپ لوگوں کو از خود مسلح جدوجہد شروع کرنے کا شرعاً کوئی حق حاصل نہیں ہے اور جہاد کے لیے کسی مسلم حکومت کی طرف سے اعلان ضروری ہے تو وہ بھی مدینہ منورہ میں کوئی علمی مرکز قائم کر کے بیٹھ جاتے اور الجزائر کی جنگ آزادی کا جو حشر ہوتا وہ ان کی بلا سے ہوتا رہتا۔
غامدی صاحب محترم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ساتویں صدی ہجری کے آخر میں عالم اسلام کے خلاف تاتاریوں کی خوفناک یلغار کے موقع پر جب دمشق کے حکمران سراسیمگی اور تذبذب کے عالم میں تھے اور عوام تاتاریوں کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو اس موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے از خود جہاد کی فرضیت کا اعلان کر کے عوام کو اس کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا تھا جس کے نتیجے میں حکمرانوں کو حوصلہ ہوا اور عوام نے شہر چھوڑنا ترک کیا۔ ورنہ اگر ابن تیمیہؒ بھی غامدی صاحب کے فلسفہ پر عمل کرتے تو بغداد کی طرح دمشق کی بھی اینٹ سے اینٹ بج جاتی۔
محترم جاوید احمد غامدی نے مولوی کے فتویٰ کے خلاف بنگلہ دیش کی کسی عدالت کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور اسے صدی کا بہترین عدالتی فیصلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ فتوؤں کا بعض اوقات انتہائی غلط استعمال کیا جاتا ہے اس لیے فتویٰ بازی کو اسلام کی روشنی میں ریاستی قوانین کے تابع بنانا چاہیے۔
بنگلہ دیش کی کون سی عدالت نے مولوی حضرات کے کون سے فتوے کے خلاف فیصلہ دیا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی مذکورہ فیصلہ ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیکن غامدی صاحب کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عدالت نے کسی مولوی صاحب کو فتویٰ دینے سے روک دیا ہوگا یا ان کے فتویٰ دینے کے استحقاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہوگا جس کی بنا پر غامدی صاحب اس کی تحسین فرما رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی یہ پسند کر رہے ہیں کہ مولویوں کو فتویٰ دینے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے اور فتویٰ بازی کو ریاستی قوانین کے تابع کر دینا چاہیے۔
جہاں تک اس شکایت کا تعلق ہے کہ ہمارے ہاں بعض فتوؤں کا انتہائی غلط استعمال ہوتا ہے، ہمیں اس سے اتفاق ہے۔ ان فتوؤں کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے غیر سرکاری سطح پر کوئی قابل عمل فارمولا سامنے آتا ہے تو ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ مگر کسی چیز کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سرے سے اس کے وجود کو ختم کر دینے کی تجویز ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ چونکہ ہماری عدالتوں میں رشوت اور سفارش اس قدر عام ہوگئی ہے کہ اکثر فیصلے غلط ہونے لگے ہیں اور عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے ان عدالتوں میں بیٹھنے والے ججوں سے فیصلے دینے کا اختیار ہی واپس لے لیا جائے۔ یہ بات نظری طور پر تو کسی بحث و مباحثہ کا خوبصورت عنوان بن سکتی ہے مگر عملی میدان میں اسے بروئے کار لانا کس طرح ممکن ہے؟ اس کے بارے میں غامدی صاحب محترم ہی زیادہ بہتر طور پر رہنمائی فرما سکتے ہیں۔
اور ’’فتویٰ‘‘ تو کہتے ہی کسی مسئلہ پر غیر سرکاری رائے کو ہیں۔ کیونکہ کسی مسئلہ پر حکومت کا کوئی انتظامی افسر جو فیصلہ دے گا وہ ’’حکم‘‘ کہلائے گا اور عدالت جو فیصلہ صادر کرے گی اسے ’’قضا‘‘ کہا جائے گا۔ جبکہ ان دونوں سے ہٹ کر اگر کوئی صاحب علم کسی مسئلہ کے بارے میں شرعی طور پر حتمی رائے دے گا تو وہ ’’فتویٰ‘‘ کہلائے گا۔ امت کا تعامل شروع سے اسی طرح چلا آرہا ہے کہ حکام حکم دیتے ہیں، قاضی حضرات عدالتی فیصلے دیتے ہیں، اور علماء کرام فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ صحابہ کرامؓ کے دور سے چلا آرہا ہے۔ خود صحابہ کرامؓ میں خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ جیسے مفتیان کرام موجود تھے جو کسی مسئلہ پر فتویٰ صادر کرنے میں کسی سرکاری نظم کے پابند نہیں تھے بلکہ آزادانہ طور پر مسائل پر رائے دیتے تھے اور ان کی رائے کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور تابعین کے دور سے تو فتویٰ کا یہ ادارہ اس قدر آزاد اور خودمختار ہوا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام وقت کی حکومتوں کے خلاف فتوے دیتے تھے اور ان فتوؤں پر مصائب و آلام بھی برداشت کرتے تھے مگر انہوں نے اپنے اس آزادانہ حق میں حکومت کی کسی مداخلت کو قبول نہیں کیا۔
طبقات ابن سعدؒ کی روایت کے مطابق رئیس التابعین حضرت حسن بصریؒ نے خلیفہ یزید بن عبد المالک کے طرز عمل پر برسرعام تنقید کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کے مظالم میں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ کامل ابن اثیرؒ کی روایت کے مطابق حضرت امام مالکؒ نے خلیفہ منصورؒ کے خلاف محمد نفس زکیہؒ کی بغاوت کی حمایت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ وہ منصورؒ کی بیعت توڑ کر محمد نفس زکیہؒ کا ساتھ دیں۔ہزارہ کی مناقب ابی حنیفہؒ میں ہے کہ امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہؒ نے محمد نفس زکیہؒ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہؒ کی مذکورہ بغاوت کی کھلم کھلا حمایت کی اور منصور خلیفہؒ کے کمانڈر حسن بن قحطبہ نے امام ابو حنیفہؒ کے کہنے پر ابراہیم بن عبد اللہؒ کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالکؒ کے دور میں اس کے خلاف امام زید بن علیؒ کی بغاوت میں بھی امام ابو حنیفہؒ نے امام زیدؒ کا ساتھ دیا اور انہیں دس ہزار درہم کا چندہ بھی بھجوایا۔
خلیفہ ہارون الرشیدؒ کے دور میں حضرت امام شافعیؒ کو بھی اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ وہ خلیفہ وقت کے خلاف یحییٰ بن عبد اللہؒ کی بغاوت کی درپردہ حمایت کر رہے ہیں مگر الزام ثابت نہ ہونے پر بعد میں رہا کر دیا گیا۔ امام مالکؒ نے ’’جبری طلاق‘‘ کے بارے میں حکومت وقت کی منشا و مفاد کے خلاف فتویٰ دیا جس پر سرعام ان پر کوڑے برسائے گئے حتیٰ کہ ان کے شانے اتر گئے۔ مگر وہ اس شان سے اپنے فتوے پر قائم رہے کہ جب انہیں گھوڑے پر سوار کر کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا تو وہ لوگوں سے بلند آواز میں کہتے جاتے تھے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں مالک بن انس ہوں اور میں نے فتویٰ دیا ہے کہ جبر کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ حکمرانوں کو امام مالکؒ کے اس فتویٰ سے خوف لاحق ہوگیا تھا کہ اگر مجبوری کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی تو جن لوگوں کو مجبور کر کے انہوں نے اپنے حق میں بیعت لے رکھی تھی کہیں وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہماری بیعت بھی واقع نہیں ہوئی اور ہم اس بیعت کے ساتھ حکمرانوں کی وفاداری کے پابند نہیں رہے۔
حکمرانوں کی مرضی اور منشا کے خلاف دیے جانے والے ان فتوؤں سے قطع نظر امت مسلمہ کے چار بڑے اماموں امام ابوحنیفہؒ ، امام مالکؒ ، امام شافعیؒ ، اور امام احمد بن حنبلؒ نے جو لاکھوں فتاویٰ صادر کیے وہ کسی سرکاری نظم اور ریاستی قوانین کا نتیجہ نہیں بلکہ شرعی مسائل پر اہل علم کی طرف سے اظہار رائے کا ایک آزادانہ نظام کا ثمرہ تھے۔ ورنہ اگر یہ ائمہ کرامؒ فتویٰ صادر کرنے میں سرکاری نظم اور ریاستی قوانین کے تابع ہونے کو قبول کر لیتے تو نہ امام ابوحنیفہؒ کا جنازہ جیل سے نکلتا، نہ امام مالکؒ سر عام کوڑے کھاتے، نہ امام شافعیؒ کی گرفتاری کی نوبت آتی، اور نہ امام احمد بن حنبلؒ کو خلق قرآن کے مسئلہ پر قید و بند اور کوڑوں کی صبر آزما سزا کے مراحل سے گزرنا پڑتا۔ ان چاروں اماموں اور ان کے علاوہ دیگر بیسیوں فقہاء اور ائمہ نے جو لاکھوں فتوے دیے اور امت کے بے شمار مسائل کا جو مفتی حل پیش کیا وہ ایک آزادانہ عمل تھا۔ اسی وجہ سے انہیں امت میں اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ آج تیرہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی امت کی غالب اکثریت ان ائمہ کے فتاویٰ پر عمل کرتی ہے اور ان کے فقہی مذاہب کی پیروکار ہے۔
امام اعظم ابوحنیفہؒ نے تو اپنی ایک مستقل ’’مجلس علمی‘‘ قائم کر رکھی تھی جس میں علماء، فقہاء، محدثین، اہل لغت اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا جمگھٹا رہتا تھا۔ یہ غیر سرکاری کونسل تھی جو مسائل پر بحث کرتی تھی، اس کے شرکاء آزادانہ رائے دیتے تھے، ان کے درمیان مباحثہ ہوتا تھا، اور جو بات طے ہوتی اسے فیصلہ کے طور پر قلمبند کیا جاتا تھا۔ اس کونسل کے فیصلے نہ صرف اس دور میں تسلیم کیے جاتے تھے بلکہ اب تک امت کا ایک بڑا حصہ ان فیصلوں پر کاربند ہے۔ امام صاحبؒ کی اس مجلس علمی یعنی غیر سرکاری کونسل کے بارے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ علوم عربی و اسلامیات کے سربراہ ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی کی مستقل کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کونسل کے خدوخال اور طریق کار کی وضاحت کی ہے۔
اس لیے فتویٰ کے آزادانہ عمل کو ریاستی قوانین کے تابع کرنے کی یہ تجویز یا خواہش امت کے چودہ سو سالہ اجتماعی تعامل کے منافی ہے جس کی کسی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور ہمارے محترم اور بزرگ دوست جاوید احمد غامدی صاحب ناراض نہ ہوں تو ڈرتے ڈرتے ان سے ایک سوال پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ انہوں نے مختلف گروپوں کی مسلح جدوجہد کے جہاد نہ ہونے، زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس کی ممانعت، اور ریاستی نظم سے ہٹ کر فتویٰ کا استحقاق نہ ہونے کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ بھی تو معروف معنوں میں ’’فتویٰ‘‘ ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں یہ فتوے جاری کرنے کی اتھارٹی کس ریاستی قانون نے دی ہے؟
توضیحات
خورشید احمد ندیم
مولانا زاہد الراشدی نے استادِ محترم جاوید احمد صاحب غامدی کے بعض نتائجِ فکر اور ’’تکبیر مسلسل‘‘ میں بیان کی گئی کچھ آرا کو اپنے مضامین کا موضوع بنایا ہے جو ایک معاصر روزنامے میں شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے چار اہم مسائل پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے جو ظاہر ہے ہمارے موقف سے مختلف اور اس پر ناقدانہ تبصرہ ہے۔ مولانا نے اپنے اختلاف کا اظہار جس سلیقے کے ساتھ کیا ہے، اس سے ہمارے دل میں ان کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ ہماری بات سے لوگ اس سے قبل بھی اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اس لہجے کو ترس گئے تھے۔ ہماری یہ خواہش کم ہی پوری ہوئی کہ لوگ علمی آرا کو علمی نظر ہی سے دیکھیں اور اسی حوالے سے ان پر اظہار خیال کریں۔ مولانا نے اس وادی میں قدم رکھا ہے تو ہم ان کے لیے سراپا شکر ہیں۔
مولانا زاہد الراشدی نے اپنے مضامین میں جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے وہ آج سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر قوم کو صحیح راہنمائی میسر آئے۔ ان مسائل پر کوئی رائے قائم کرتے وقت اگر ہم نے ٹھوکر کھائی یا کسی ابہام کا شکار ہوئے تو اس سے ہماری اجتماعی زندگی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ مولانا نے اس سلسلہ مضامین کے آغاز میں ہمارا فکری شجرہ نسب بھی بیان کیا ہے، اس میں دو باتیں وضاحت کی طلب گار ہیں۔ آج کا کالم انہی کی توضیح کے لیے خاص ہے، جہاں تک اصل مسائل کا تعلق ہے تو وہ اگلے کالموں میں ایک ترتیب سے زیربحث آئیں گے۔
پہلی بات خبرِ واحد کی حجیت کے بارے میں ہے، اس باب میں محدثین اور فقہا کا اختلاف معروف ہے، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ہنوز یہ بحث زندہ ہے۔ ہمارے مکتبہ فکر کے نزدیک فہمِ دین کے جو اصول ہیں وہ اگر پیشِ نظر ہوں تو یہ بحث قطعاً غیر اہم ہو جاتی ہے۔ محترم جاوید صاحب نے ’’اصول و مبادی‘‘ کے عنوان سے انہیں بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے:
’’سنت سے مراد دینِ ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے‘‘۔یہ سنت چالیس امور پر مشتمل ہے۔ ’’اس کے بارے میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہؓ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماعی اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے‘‘۔ (اشراق ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۹ء)
سنت کی یہ تعریف اگر سامنے ہو تو نہ صرف اخبار آحاد کی حجیت کا سوال باقی نہیں رہتا بلکہ سنت کے ماخذ دین ہونے پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
دوسری بات کا تعلق رجم کے بارے میں مولانا امین احسن اصلاحی کی رائے سے ہے۔ زنا کی سزا کے حوالے سے مولانا کا موقف یہ ہے کہ اس کے نفاذ میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تمیز روا نہیں رکھی جائے گی۔ قرآن مجید جب اس جرم کے لیے سو کوڑوں کی سزا بیان کرتا ہے تو وہ مجرم کی ازدواجی حیثیت کو زیربحث نہیں لاتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا کی یہ رائے جمہور کے موقف سے مختلف ہے لیکن وہ کبھی اس بات کے علمبردار نہیں رہے کہ ریاست کا قانون ان کی رائے پر مبنی ہو۔
اس باب میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک مسلمان ریاست میں پبلک لا اسی رائے کی بنیاد پر بنایا جائے جس پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتماد ہو۔ اگر پاکستان میں لوگوں کی اکثریت ان علما کی رائے سے اتفاق کرتی ہے جو ہم سے مختلف الرائے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ انہی کی رائے کو قانون سازی کے وقت پیشِ نظر رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اہلِ علم کو بہرحال یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ علمی طور پر اگر کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں تو اسے آزادی سے بیان بھی کر سکیں۔ اگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت ان کی رائے پر اعتماد کرنے لگتی ہے تو پھر خودبخود اسے یہ حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ اسے ریاست کا قانون بنا دیا جائے۔
یہ بات واقعاتی طور پر درست نہیں ہے کہ مولانا کبھی وفاقی شرعی عدالت گئے اور انہوں نے رجم کے شرعی حد نہ ہونے پر دلائل فراہم کیے۔ امرِ واقعہ یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ’’تدبر قرآن‘‘ کا وہ حصہ چھپ چکا تھا جس میں مولانا نے اپنی رائے بیان کی ہے۔ عدالت نے اسی سے استفادہ کیا تھا۔ مولانا اصلاحی نہ صرف یہ کہ کسی عدالت میں نہیں گئے بلکہ جاوید صاحب نے تو جسٹس آفتاب حسین سے یہ کہا کہ وہ اپنے فیصلے کی بنیاد اس رائے پر رکھیں جس پر اکثریت اعتماد کرتی ہے۔
ہمارا تو اس بات پر اصرار رہا ہے کہ اہلِ علم کو اپنی رائے دینے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اس کے نفاذ یا دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی دوسرا ان سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا یہ حق تسلیم کرنا چاہیے۔ اس باب میں ہم تو امام مالک کے مقلد ہیں، خلیفہ منصور نے جب ان کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کی موطا کو ریاست کا قانون بنانا چاہتا ہے تو انہوں نے منصور کی تائید نہیں کی اور کہا کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ جس رائے کو چاہیں گے اختیار کر لیں گے۔
یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں جو فقہی مکاتبِ فکر مقبول ہوئے ان کے فروغ میں اقتدار کا ایک حصہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے کہ جب معاشرہ کسی صاحبِ علم پر اعتماد کرنے لگتا ہے تو پھر صاحبانِ اقتدار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس کی رائے کے برخلاف فیصلہ دیں۔ مامون الرشید کے وزیر فضل بن سبل کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ عدالتوں کو اس بات سے روک دیا جائے کہ وہ ابوحنیفہ کی رائے کی بنیاد پر فتوٰی دیں۔ اس نے مشاورت کے لیے اہلِ علم و دانش کو جمع کیا، سب کی رائے یہ تھی کہ اس اقدام کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ لوگ عباسی حکمران پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے اقتدار کا سلامت رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں نے فضل سے یہ بھی کہا کہ جس نے آپ کو یہ رائے دی وہ کوئی احمق شخص ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی صاحبِ علم آج بھی اگر امام ابوحنیفہ کے طرز عمل کی تقلید کرے تو ایسے ہی نتائج نکل سکتے ہیں۔
ہمارا اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی بات بزور دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو اپنے نامہ اعمال میں جلی حروف سے درج کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں فتنے کے خلاف جہاد کیا۔ ہم اختلاف کرنے والے کو پہلے دائرہ اسلام اور پھر دائرہ حیات سے خارج کرنے کے لیے کمربستہ ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں پر قبضے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے اور دوسروں کے لیے جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جتنی محنت ہم لوگوں کو کافر قرار دینے کے لیے کرتے ہیں اگر اتنی ہی مشقت ہم انہیں مسلمان بنانے کے لیے اٹھائیں تو دنیا کا منظر بہت بدل جائے۔
مولانا زاہد الراشدی نے اہم مسائل کو سنجیدہ بحث کا موضوع بنایا ہے، اللہ کرے کہ ہم بحیثیت قوم ان مسائل پر زیادہ سے زیادہ اتفاقِ رائے پیدا کر سکیں۔
علما اور سیاست
کیا علما کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے وقت دو باتیں پیش نظر رہنا چاہییں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شریعت کا نہیں، حکمت وتدبر کا معاملہ ہے۔ یہ جائز اور ناجائز کی بحث نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے علما کو سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا ہے یا انہیں اس کے لیے حکم دیا ہے۔ جب ہم اس سوال کو موضوع بناتے ہیں تو ہمارے پیش نظر محض یہ ہے کہ اس سے دین اور علما کو کوئی فائدہ پہنچا ہے یا نقصان؟ دوسری بات یہ کہ عملی سیاست سے ہماری مراد اقتدار کی سیاست (Power Politics) ہے یعنی اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا یا کسی کے عزل ونصب کے لیے کوئی عملی کردار ادا کرنا۔
قرآن مجید کی راہنمائی یہ ہے کہ ایک عالم دین کا اصل کام انذار کرنا ہے۔ (توبہ :۱۲۲) انذار یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ انہیں ایک روز اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور ان اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے جو وہ اس دنیا میں سرانجام دیں گے۔ اس جواب دہی کا تعلق اس کردار کے ساتھ ہے جو وہ اس دنیا میں ادا کریں گے۔ اگر کوئی حکمران ہے تو اس کی جواب دہی کی نوعیت اور ہے، اور اگر ایک عامی ہے تو اس کے لیے اور۔ اسی انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ علما دین کو اس طرح بیان کریں جیسے کہ وہ ہے۔ اگر دین کو کوئی فکری چیلنج درپیش ہے تو وہ دین کا مقدمہ لڑیں۔ اگر مسلمان معاشرے میں کوئی علمی یا عملی خرابی در آئی ہے تو وہ اسے اصل دین کی طرف بلائیں۔ اس معاملے میں ان کی حیثیت ایک داروغہ کی نہیں ہے۔ انہیں دین کا ابلاغ کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ اس کی ایک صورت ایسے مبلغین کی تیاری ہے جو اس کام کو لے کر معاشرے میں پھیل جائیں اور ایسے ادارے اور دار العلوم آباد کرنا ہے جہاں دین کے جید عالم تیار ہوں۔ اس انذار کی ایک شکل عامۃ الناس کا تزکیہ بھی ہے۔ یہ تزکیہ علم کا بھی ہوگا اور عمل کا بھی۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے صوفیا کرتے رہے ہیں۔ اس وقت تصوف ایک فلسفہ حیات کے طور پر زیر بحث نہیں ہے۔ میں جس پہلو کی تحسین کر رہا ہوں، وہ صوفیانہ حکمت عملی ہے جو خانقاہوں اور صوفیا کے حلقوں میں اختیار کی گئی ہے۔
تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ علما نے جب یہ کام کیا، معاشرے پر اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے۔ ان اثرات کا دائرہ اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عامۃ الناس کے حجروں تک پھیلا ہوا ہے۔ مختلف تذکروں میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جب حکمران، علما کے حجروں میں حاضر ہیں یا علما ارباب اقتدار سے بے نیازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ علما کو اگر معاشرے میں یہ مقام حاصل تھا تو اس کا سبب یہ تھا کہ وہ انذار کے منصب پر فائز تھے۔ انہوں نے خود کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیا تھا کہ وہ دین بیان کریں گے اور معاشرے کے مختلف طبقات کو ان کی دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کریں گے۔ یہ لوگ کبھی اقتدار کی کشمکش میں فریق نہیں بنے۔ معاشرے پر ان کے اثرات کا یہ عالم تھا کہ حکمران ان کی رائے کے احترام پر مجبور تھے۔ پھر یہ وقت بھی آ گیا کہ ایسے لوگ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے جن پر کسی صاحب علم کا خاص اثر تھا۔ اس نے برسر اقتدار آ کر ان کی رائے کو ریاست کا قانون بنا دیا۔ ہارون الرشید نے قاضی ابو یوسف کو قاضی القضاۃ بنا دیا۔ محکمہ قضا جب ان کے ہاتھ آیا تو اسلامی ریاست میں اسی کو قضا کے عہدے پر فائز کیا جاتا جس کی سفارش قاضی ابو یوسف کرتے تھے۔ افریقہ میں معز بن باولیس کو والی بنایا گیا تو امام مالک کی فقہ کو وہاں غلبہ حاصل ہو گیا۔ اندلس میں حکم بن ہشام کے دور میں فقہ مالکی کو سرکاری حیثیت مل گئی۔ مصر میں صلاح الدین یوسف بن ایوب جب عبید کو شکست دے کر حکمران بنے تو فقہ شافعی کو غلبہ ملا کیونکہ بنو ایوب شوافع تھے۔ اب کسی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں فقہ حنفی کے لیے مہم چلائی گئی ہو یا حنبلی مسلک کے نفاذ کا مطالبہ لے کر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔
ہم جن صاحبان عزیمت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ تذکرہ ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث بنتا ہے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اقتدار کی کشمکش میں کبھی فریق نہیں تھے۔ انہوں نے حکمرانوں سے اگر اختلاف کیا تو اس موقع پر جب انہوں نے دین میں مداخلت کی یا شریعت کے کسی حکم کو تبدیل کرنا چاہا۔ عباسی حکمرانوں نے جب یہ حکم جاری کیا کہ جو ان کی بیعت سے نکلے تو اس کی بیوی خود بخود اس پر حرام ہو جائے گی تو یہ فرمان دین میں مداخلت تھا چنانچہ امام مالکؒ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس جبری طلاق کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ نے اگر حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی تو اس بات پر کہ وہ ریاست کی قوت کو بروئے کارلا کر یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کو مخلوق مانا جائے۔ علما اور فقہاے امت کا یہ کام اپنی حقیقت میں انذار ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں دین کے کسی حکم کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے دین کا صحیح تصور پیش کریں۔ یہ کوئی سیاسی کردار نہیں ہے۔ ان لوگو ں نے حکمرانوں کے ناپسندیدہ کاموں پر انہیں ٹوکا لیکن نہ خود کو ان کی اطاعت سے آزاد کیا نہ دوسرے لوگوں کو اس کے لیے کہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان جلیل القدر لوگوں کو اس راہ میں بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑیں لیکن اس کے بعد ارباب اقتدار کے لیے یہ آسان نہیں رہا کہ وہ اپنی رائے پر اصرار کریں۔
آج بھی اگر کوئی ایسی صورت حال پیش آتی ہے تو یہ علما کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا دفاع کریں اور اس راہ میں کوئی مشقت اٹھانا پڑتی ہے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ صبر واستقامت ایسی چیزیں نہیں ہیں جو رائیگاں چلی جائیں۔ جو لوگ ان خوبیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاشرے پر ان کے بے پناہ اثرات ہوتے ہیں۔ آج کے جمہوری دور میں تو حکمرانوں کے لیے مزید مشکل ہو جائے اگر وہ ایسے لوگوں کی مخالفت کریں۔
اسی بنیاد پر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ علما کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اقتدار کی حریصانہ کشمکش سے دور رہ کر منصب اعلیٰ کو آباد کریں اور دین کی حفاظت کے ساتھ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ اس سے دین کو فائدہ پہنچے گا اور ان کے احترام میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے ان کا سیاسی اثر ورسوخ بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ میں پاکستان کے کئی ایسے علما وصوفیا کے نام گنوا سکتا ہوں جو اپنی خانقاہوں سے کبھی نہیں نکلے لیکن ان کے معاشرتی اثرات کا یہ عالم ہے کہ ہر عام انتخابات کے موقع پر اہل سیاست ان کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے تائید کی بھیک مانگتے ہیں۔ وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دیں، ان کے حلقہ اثر میں اس کی کام یابی یقینی ہو جاتی ہے۔
یہ صحیح ہے کہ تاریخ میں ہمیں بعض ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اقتدار کی کشمکش میں فریق تھے۔ پرانے دور میں اس کی نوعیت خروج کی تھی۔ امام ابن تیمیہؒ نے ’’منہاج السنۃ‘‘ میں ان تمام بغاوتوں کا جائزہ لے کر یہ بتایا ہے کہ ایسی کوئی کوشش نہ صرف یہ کہ کامیاب نہیں ہوئی بلکہ اس سے امت میں انتشار اور افتراق کا ایسا دروازہ کھلا کہ پھر کبھی بند نہیں ہو سکا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں اگرچہ صاحبان اقتدار کی تبدیلی کے انداز بدل گئے ہیں لیکن علما کی عملی سیاست میں شرکت کے نتائج پر کوئی فرق نہیں آیا۔ پاکستان کو اگر ہم اپنی توجہ کا مرکز بنائیں تو علما کی سیاست کا دین کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا۔
پاکستانی سیاست میں علما کا کردار
پاکستان میں علما عملی سیاست میں بالعموم دو طرح سے شریک رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بعض مذہبی ودینی مسائل پر تحریکیں اٹھائیں اور مطالبات منوانے کے لیے اپنی سیاسی قوت کو بروئے کار لائے۔ دوسری صورت میں یہ دھماکہ انہوں نے خود کو قوم کے سامنے متبادل قیادت کے طور پر پیش کر کے کیا اور مروجہ نظام کے تحت اقتدار تک پہنچنے کی سعی کی۔ ان دونوں صورتوں کے جو نتائج نکلے، میں انہیں قدرے تفصیل کے ساتھ زیر بحث لا رہا ہوں۔
تحریکیں اٹھا کر علما نے بعض مذہبی معاملات میں حکومت وقت سے قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ مثال کے طور پر ۱۹۴۸ء میں دستور اسلامی کے لیے تحریک اٹھی، ۱۹۵۳ء اور پھر ۱۹۷۴ء میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ۱۹۷۳ء کے آئین کو اسلامی بنانے کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ ان مخصوص مسائل کے علاوہ بھی ہمارے علما ہر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ وہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے۔ گزشتہ دنوں میں ان کی طرف سے اسلام آباد پر یلغار کا اعلان تھا۔ یہ اقدام بھی اس مطالبہ پر مبنی تھا کہ حکومت فوری طور پر نفاذ اسلام کا اعلان کرے۔ علما کی یہ مہم بڑی حد تک کام یاب رہی۔ قانون سازی کے باب میں ان کے مطالبات بالعموم تسلیم کر لیے گئے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قانون کی سطح پر پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں اب کوئی امر مانع نہیں ہے۔ یہ البتہ ایک دوسری بحث ہے کہ محض قانون سازی سے کیا کوئی ریاست اسلامی بن سکتی ہے؟
اب ہم دوسری صورت کی طرف آتے ہیں۔ اس ملک میں اقتدار تک پہنچنے کے دو راستے ہیں: ایک آئینی، دوسرا غیر آئینی۔ آئینی طور پر برسراقتدار آنے کا واحد راستہ انتخابات ہیں۔ ہماری مذہبی جماعتوں نے انتخابات میں دو طرح سے حصہ لیا۔ انفرادی حیثیت میں اور سیاسی اتحادوں میں شامل ہو کر۔ انفرادی سطح پر انتخابات میں حصہ لے کر علما نہ صرف کوئی قابل ذکر کام یابی حاصل نہ کر سکے بلکہ ان کی حمایت میں بتدریج کمی آئی۔ ۱۹۷۰ء میں انہیں پندرہ فیصد رائے دہندگان کا اعتماد حاصل تھا تو ۱۹۹۷ء تک پہنچتے پہنچتے اس میں بہت کمی آگئی۔ تاہم اتحادوں میں شامل ہو کر وہ پارلیمنٹ تک پہنچے اور بعض اوقات صوبائی اور قومی سطح پر شریک اقتدار بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ شرکت اسی وقت ممکن ہوئی جب انہوں نے کسی بڑی سیاسی جماعت کا ہاتھ تھاما۔
یہ تو علما کی سیاست کے براہ راست نتائج ہیں۔ اب ہم ان نتائج کی طرف آتے ہیں جو بالواسطہ سامنے آئے۔
پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اقتدار کی حریصانہ کشمکش میں شریک ہو کر وہ منصب دعوت سے معزول ہو گئے۔ اب وہ معاشرے میں دین کے داعی کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے۔ دعوت بے غرض بناتی ہے اور سیاست غرض مند۔ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو جواباً کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اس سے آپ کی قدر ومنزلت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ آپ کی دعوت کے کیا اثرات مدعو پر پڑیں گے، اس کو آپ کی بات پسند آئے گی یا نہیں۔ اس کے بالمقابل جب آپ سیاست میں ہیں تو لوگوں سے ووٹ کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ یہ ایک ضرورت مند کا کردار ہے۔ آپ کو حق بات کہنے سے زیادہ دلچسپی اس امر میں ہے کہ عوام کے مطالبات کیا ہیں؟ چنانچہ کسی سیاسی ضرورت کے تحت آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ موزوں ترین شخص ہیں جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ جو یہ بات باور کرانے میں کام یاب ہو جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کی حریصانہ کشمکش میں جب آپ فریق بنتے ہیں تو پھر وہ گروہ آپ کا مخاطب نہیں رہتا جو آپ کا مخالف ہے۔ اس طرح آپ کی دعوت اس طبقے تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ بات حکمت تبلیغ کے خلاف ہے لہٰذا علما کی سیاست کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ مسند دعوت خالی ہو گیا۔
دوسرے نتیجے کا تعلق مذہبی جماعتوں کی ہیئت ترکیبی سے ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی کے استثنا کے ساتھ، فرقہ وارانہ بنیاد پر قائم ہیں۔ ہر مسلک کے علما نے اپنی سیاسی جماعت بنا رکھی ہے۔ سیاست کے مبادیات سے واقف ایک شخص بھی یہ جانتا ہے کہ جو جماعت کسی خاص مذہبی فکر پر قائم ہو، وہ کبھی قومی جماعت نہیں بن سکتی۔ اس کے ساتھ ان مذہبی عناصر کے مفاد کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ تقسیم باقی رہے کیونکہ اس صورت میں انہیں ایک پریشر گروپ کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ کسی بڑی سیاسی جماعت سے معاملہ کر کے سینٹ یا اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح سیاسی منظر پر اپنی موجودگی کو یقینی بناتے ہیں۔ اس سے کسی فرد واحد یا چند افراد کو تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچتا ہے لیکن قوم میں مسلکی تقسیم مزید پختہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ ان عناصر کے پیش نظر شخصی مفاد ہوتا ہے اس لیے ایک لازمی نتیجے کے طور پر شخصیات کا تصادم (Personality clash) جنم لیتا ہے اور یہ جماعتیں مزید تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتی ہیں۔ آج اس ملک میں کوئی مذہبی جماعت ایسی نہیں جو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں منقسم نہ ہو۔ گویا اس مذہبی سیاست کا دوسرا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ فرقہ وارانہ گروہ بندی مضبوط تر ہو گئی۔
تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست میں مسلسل ناکامیوں نے ان لوگوں کو مایوسی (Frustration) کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ چنانچہ اب وہ برملا یہ کہنے لگے ہیں کہ انتخابی سیاست سے کام یابی کا کوئی امکان نہیں اس لیے ہمیں اب کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا کیونکہ آئین کے تحت تبدیلی کا واحد راستہ انتخابات ہیں۔ یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تبدیلی کے لیے مسلح جدوجہد کے قائل ہیں۔
چوتھا نتیجہ یہ نکلا کہ عملی سیاست میں شریک بعض علما کے دامن پر جب دنیاوی آلودگیوں کے نشانات کا تاثر ابھرا تو اس سے علما کی شہرت کو بالعموم بہت نقصان پہنچا۔ میرے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ اس تاثر میں صداقت کا تناسب کیا ہے لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تاثر پیدا ہی تب ہوا جب علما عملی سیاست میں الجھے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ دور جدید میں علما کا وقار جتنا مجروح ہوا ہے، شاید ہی کسی دوسرے طبقے کا ہوا ہو۔ دنیا داروں کے ساتھ جب انہوں نے معاملات کیے تو علما کو ان کی سطح پر اترنا پڑا۔
میرے نزدیک ان نتائج کی فہرست طویل ہو سکتی ہے لیکن اگر محض ان ہی کو پیش نظر رکھا جائے تو یہی رائے بنتی ہے کہ عملی سیاست دین اور علما دونوں کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئی۔ علما کی عملی سیاست میں شرکت کا واحد فائدہ یہ ہوا کہ یہ ملک آئینی اور دستوری طور پر اسلامی بن گیا۔ اس کے علاوہ اس شرکت کے تمام نتائج منفی رہے۔ اب جہاں تک اس واحد فائدے کا تعلق ہے تو علما اگر اپنے منصب انذار پر جلوہ افروز رہتے اور حکمرانوں کو اس جانب متوجہ کرتے کہ اگر کسی خطے میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ شرعاً اس کے پابند ہیں کہ وہاں اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو تو بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا۔ یہ قوم مزاجاً بھی ریاست کے سیکولر تشخص کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر علما کا یہ دباؤ بھی ہوتا تو کوئی حکومت یہ جرات نہ کر سکتی کہ وہ پاکستان کو دستوری طور پر سیکولر بنائے۔ پھر اس بات سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ دستور کو اسلامی بنانے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے میں بنیادی کردار ایک ایسے عالم دین، مولانا ظفر احمد انصاری مرحوم کا تھا جو عملی سیاست سے دور رہنے والے تھے۔
اس تجزیے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ اس سے مقصود دین وسیاست کی علیحدگی کی وکالت ہے۔ یہاں محض یہ بات کہی جا رہی ہے کہ علما کا کام سیاست نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے سیاست کا رجحان رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے اور اس میں بھی دو آرا نہیں کہ اس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے لیکن ہمارے نزدیک یہ کام وہ لوگ کریں جن کے اندر اس کے لیے فطری داعیہ موجود ہو۔ علما کا منصب یہ نہیں کہ وہ سیاست دان بنیں۔ ان کاکام یہ ہے کہ وہ سیاست دانوں کو مسلمان بنائیں۔ اس ملک میں تنہا مولانا مودودیؒ کے عالمانہ کام کا یہ اثر ہے کہ اہل صحافت کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی جس کی تمام صحافیانہ سرگرمیوں کا محور ومرکز یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے۔ اگر مولانا سیاست کی حریفانہ کشمکش کو بھی اسی طرح متاثر کرتے، ذرا غور کیجیے اگر ہمارے درمیان ایسے علما موجود ہوتے جن کی علمی وجاہت سے اس ملک کا رجحان ساز طبقہ یعنی اہل سیاست، فوجی قیادت، بیورو کریسی مرعوب ہوتے تو اس ملک کا نقشہ کیا ہوتا؟ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر علما اپنی ذمہ داری بطریق احسن ادا کرتے تو آج ہمیں حکمرانوں سے نفاذ اسلام کی بھیک نہ مانگنا پڑتی۔
غامدی صاحب اور خبرِ واحد
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
علماء کے سیاسی کردار، کسی غیر سرکاری فورم کی طرف سے جہاد کے اعلان کی شرعی حیثیت، علماء کرام کے فتویٰ جاری کرنے کے آزادانہ استحقاق، اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور ٹیکس کی شرعی ممانعت کے حوالہ سے محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے بعض حالیہ ارشادات کے بارے میں ان کالموں میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ ہمارا خیال تھا کہ غامدی صاحب محترم ان مسائل پر قلم اٹھائیں گے اور ہمیں ان کے علم و مطالعہ سے استفادہ کا موقع ملے گا۔ لیکن شاید ’’پروٹوکول‘‘ کے تقاضے آڑے آگئے جس کی وجہ سے غامدی صاحب کی بجائے ان کے شاگرد رشید خورشید احمد ندیم صاحب نے ہماری ان گزارشات پر قلم اٹھایا اور معاصر روزنامہ جنگ میں ’’تکبیر مسلسل‘‘ کے عنوان سے شائع ہونے والے مضامین میں انہوں نے ان مسائل پر اظہار خیال کا سلسلہ شروع کیا ہے۔
اس سلسلہ میں قارئین کی یہ الجھن ہمارے پیش نظر ہے کہ ہماری گزارشات اور خورشید احمد ندیم صاحب کی جوابی توضیحات الگ الگ اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں اور بہت سے قارئین کے لیے دونوں کا مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اگر دونوں اخبارات اپنے صفحات میں شائع ہونے والے ان مضامین کے جواب میں سامنے آنے والے مضامین کو بھی اپنے صفحات میں جگہ دے دیں تو اس سے دونوں روزناموں کے قارئین کو پوری بحث سے استفادہ کا موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ اخبارات کے منتظمین کا مسئلہ ہے اور وہ اپنی مصلحتوں اور ضرریات کو زیادہ بہتر طو رپر سمجھتے ہیں کہ
رموز مملکت خویش خسروان دانند
بہرحال اب تک خورشید احمد ندیم نے دو نکات پر گفتگو کی ہے۔ پہلے مرحلہ میں انہوں نے توضیحات کے عنوان سے خبر واحد کے حجت ہونے کے بارے میں ہماری گزارش پر تبصرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے ہاں سنت کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اسے پیش نظر رکھا جائے تو خبر واحد کے حجت ہونے یا نہ ہونے کی بحث کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ مگر ہمیں خورشید صاحب کے اس ارشاد سے اختلاف ہے جس کا آئندہ سطور میں ہم ذکر کریں گے لیکن اس سے قبل ہم خبر واحد کے بارے میں عام قارئین کے لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ صحیح طور پر اس بحث کو سمجھ سکیں۔
’’خبر واحد‘‘ کا لفظی معنٰی ایک آدمی کی روایت ہے۔ اور محدثین کی اصطلاح میں خبر واحد اسے کہتے ہیں کہ قرون اولیٰ یعنی صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے دور میں کسی حدیث نبویؐ کو روایت کرنے میں ایک ہی بزرگ متفرد ہوں اور دوسرا کوئی ان کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے میں شریک نہ ہو۔ ایسی خبر کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف چلا آرہا ہے کہ شرعی احکام کے ثبوت میں یہ خبر اور حدیث حجت ہے یا نہیں۔ جمہور محدثین اور فقہاء کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی ثقہ راوی کی روایت کردہ خبر واحد اگر قرآن کریم کی کسی نص صریح کے خلاف نہیں اور کوئی خبر متواتر یا اجماعی تعامل بھی اس کی نفی نہیں کر رہا تو وہ شرعاً حجت ہے اور اس پر عمل واجب ہے۔ مگر بعض اصولی فقہاء کا موقف یہ ہے کہ خبر واحد کسی شرعی حکم کے وجوب کا فائدہ نہیں دیتی۔
ہم نے ایک سابقہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ مولانا امین احسن اصلاحیؒ اور جناب جاوید احمد غامدی کے مکتب فکر کا موقف ان اصولی فقہاء کے قریب ہے۔ اسی وجہ سے انہیں شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کا مرتکب قرار پانے پر اس کے لیے سنگسار کرنے کی سزا کو ’’شرعی حد‘‘ کے طور پر قبول کرنے میں تامل ہے۔ اس کے جواب میں خورشید ندیم صاحب کا ارشاد ہے کہ سنت رسولؐ کے بارے میں غامدی صاحب کی وضاحت کو سامنے رکھنے کے بعد خبر واحد کی حجت کا سوال باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ اس ضمن میں غامدی صاحب کے دو ارشادات نقل کر رہے ہیں کہ
(۱) ’’سنت سے مراد دین ابراہیمی ؑ کی وہ روایت ہے جسے نبی اکرمؐ نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔‘‘
(۲) ’’اس بارے میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں وہ جس طرح صحابہؓ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے یہ اسی طرح ان کے اجتماع اور عملی تواتر سے ملی ہے اور ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے۔‘‘
ہم ان دو اقتباسات کا جو مطلب سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ سنت صرف وہی ہے جو دین ابراہیمیؑ کے سابقہ تسلسل کے ساتھ نقل ہوتی چلی آرہی ہے اور جناب نبی اکرمؐ نے تجدید و اصلاح کے ساتھ اسے باقی رکھا ہے۔ اس کا لازمی مطلب اگر سامنے رکھا جائے تو جناب نبی اکرمؐ کا ہر وہ عمل اور قول سنت کے دائرہ سے نکل جاتا ہے جس کا دین ابراہیمیؑ کے سابقہ تسلسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور رسول اکرمؐ نے اپنی طرف سے نئی سنت کے طور پر اس کا اجراء فرمایا ہے۔ اسی طرح کسی سنت کے ثبوت کے لیے غامدی صاحب کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد امت کے اجماع اور قولی تواتر سے ثابت ہو۔ اور جو سنت نبویؐ یا حدیث رسولؐ اجماع اور تواتر کے ذریعہ ہم تک نہیں پہنچی وہ غامدی صاحب کے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہے۔
لہٰذا اگر حدیث و سنت کے تعین اور ثبوت کے لیے اس معیار کو قبول کر لیا جائے تو چوہدری غلام احمد پرویز اور ان کے رفقاء کی طرح حدیث و سنت کے انکار کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ بلکہ اس وقت حدیث و سنت کے نام سے روایات کا جو ذخیرہ امت کے پاس موجود ہے اور جس کی چھان پھٹک کے لیے محدثین تیرہ سو برس سے صبر آزما اور جاں گسل علمی جدوجہد میں مصروف چلے آرہے ہیں اس کا کم و بیش نوے فیصد حصہ خود بخود سنت کے دائرے سے نکل کر کالعدم قرار پا جاتا ہے۔ ہمیں تعجب اس بات پر ہے کہ خورشید احمد ندیم صاحب ان اقتباسات کے ذریعہ خبر واحد کے حجت ہونے بلکہ سرے سے اس کے بیشتر کو سنت تسلیم کرنے سے انکار فرما رہے ہیں، مگر انہیں اس بات پر بھی اصرار ہے کہ سنت کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھنے کے بعد خبر واحد کے حجت ہونے یا نہ ہونے کے اختلاف کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔
ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک خبر واحد بلکہ اجماع اور تواتر کے ذریعہ ثابت نہ ہونے والی کسی بھی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر امت کے جمہور محدثین اور فقہاء کے نزدیک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ ارشاد اور عمل پوری اہمیت رکھتا ہے جو اہل علم کے طے کردہ اصولوں کے مطابق ثقہ اور مستند راویوں کے ذریعہ امت تک پہنچا ہے اور جسے محدثین صحیح روایت کے طور پر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
لطف کی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب اور خورشید ندیم صاحب کے نزدیک کسی ایک سنت کے ثبوت کے لیے تو صحابہ کرامؓ اور امت کا اجتماعی تعامل ضروری ہے، لیکن اسی سنت کے مفہوم کے تعین، روایت کے طریق کار، قبولیت کے معیار، اور صحت و ضعف کے قواعد و اصول کے بارے میں امت کے چودہ سو سالہ اجتماعی تعامل اور جمہور محدثین و فقہاء کا طرز عمل ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ امت کے جمہور اہل علم کے طے کردہ اس معیار کو قبول کرنے کی بجائے اپنے ’’جداگانہ اصولوں‘‘ کو حتمی معیار کے طور پر پیش کرنے پر مصر ہیں۔ اور اس معاملہ میں اجتماع و تواتر اور تفرد و توحد کا فرق ان کے ذہن تک رسائی کا راستہ پانے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔
علماء اور سیاست
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
خورشید احمد ندیم صاحب نے علماء کے سیاسی کردار پر تفصیلی بحث کی ہے اور اس نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے کہ علماء کرام کو عملی سیاست میں براہ راست رفیق بننے کی بجائے اصولی سیاست اور رہنمائی کی سطح تک اپنی سرگرمیوں کو محدود رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی پاکستان کی پچاس سالہ سیاست کا تجزیہ کیا ہے کہ علماء کا عملی سیاست میں حصہ لینا علماء اور دین دونوں کے لیے فائدہ کی بجائے نقصان کا باعث بنا ہے۔
جہاں تک علماء کے عملی سیاست میں فریق بننے یا نہ بننے کی بات ہے خورشید ندیم صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جائز و ناجائز کی بات نہیں بلکہ حکمت و تدبیر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس حوالہ سے ان کے موقف اور ہمارے موقف میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا کیونکہ ہم نے بھی ’’موقع محل کی مناسبت‘‘ کے عنوان سے ضرورت کے وقت عملی سیاست میں علماء کے فریق بننے کا دفاع کیا تھا۔ جبکہ انہوں نے اسے ’’حکمت و تدبیر‘‘ کا نام دے دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حکمت و تدبیر نہ تو ایسی جامد شے ہے کہ ہر وقت ایک ہی حالت اور کیفیت میں رہے اور نہ ہی اس کی سطح ہر طبقہ، زمانہ اور علاقہ کے لیے یکساں رہتی ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اس سے ایک ہی طرح کا نتیجہ برآمد ہو۔ اس لیے ہم بھی اس بحث کو آگے نہیں بڑھا رہے کیونکہ بے مقصد بحث اور لفظی نزاع کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
البتہ ہم اپنی اس گزارش کا اعادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ قومی زندگی میں علماء کا اصل مقام علمی رہنمائی اور فکری قیادت ہے، اور عملی سیاست میں براہ راست فریق نہ بننے کی صورت میں وہ زیادہ بہتر طور پر اپنی ذمہ داری کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت حکمت و تدبیر کے تقاضے یا موقع محل کی مناسبت سے وہ شرح صدر کے ساتھ عملی سیاست میں خود سامنے آنے کو ضروری سمجھتے ہوں تو ان کے لیے شرعاً یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں ان کے لیے حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ، حضرت امام ابو حنیفہؒ ، حضرت امام مالکؒ ، شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ ، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ جیسے زعمائے امت کا واضح اسوہ اور شاندار روایات موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں عملی سیاست میں نہ صرف دخل دیا بلکہ اس کے لیے گروہ بندی کی، محاذ آرائی کے دور سے گزرے، اور تاریخ میں قربانی و ایثار اور استقلال و استقامت کے روشن باب قائم کیے۔
مگر خورشید ندیم صاحب کے تجزیہ کے دوسرے حصے یعنی پاکستان میں علماء کے سیاسی کردار کے حوالے سے ان کی رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے عملی سیاست میں علماء کرام کے فریق بننے کے جو نقصانات گنوائے ہیں وہ ہمارے سامنے بھی ہیں اور ان میں سے بعض باتوں سے ہمیں اتفاق ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ عملی سیاست میں حصہ لے کر علماء کرام ’’دعوت کے منصب‘‘ سے معزول ہوگئے ہیں۔ کیونکہ ہماری نصف صدی کی تاریخ میں بھی ماضی کی طرح یہ دونوں دائرے الگ الگ رہے ہیں اور آج بھی الگ الگ ہیں۔
دینی جدوجہد کی یہ فطری تقسیم کار چودہ سو سال سے چلی آرہی ہے کہ علمی کام کرنے والے خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہیں، دعوت و اصلاح کے مرد میدان اپنے محاذ پر مصروف کار ہیں، اور تحریکی مزاج کے اہل علم و دین کا اپنا میدان کار ہے۔ پاکستان کی باون سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ تمام شعبے یہاں بھی اپنے دائرہ کار میں مصروف دکھائی دیں گے اور ان میں باہمی تعاون کی ایک خاموش روش بھی نظر آئے گی۔ ملک میں ایسے اصحاب علم کی ایک بڑی تعداد آج بھی موجود ہے جو عملی سیاست کے جھمیلوں میں پڑے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور عوامی سطح پر دین کی طرف بنیادی دعوت کا عمل بھی موجود ہے جو عملی سیاست سے الگ تھلگ رہ کر دین کی چند بنیادی باتوں کو ہر مسلمان کے ذہن میں ڈالنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا خورشید ندیم صاحب کی ’’حکمت و تدبیر‘‘ اس تقسیم کار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور کیا ان کے نزدیک ’’حکمت و تدبیر‘‘ اسی کا نام ہے کہ علم و دانش سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کو ایک ہی طرح کے کام میں لگا دیا جائے اور تمام اذہان و افکار کو ایک ہی سطح، ایک ہی دائرہ اور ایک ہی رخ کا پابند بنا کر باقی ہر کام کی نفی کر دی جائے؟ ہم خورشید ندیم صاحب محترم سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ عملی سیاست میں فریق بننے والے علماء کی محدود تعداد کو سامنے رکھ کر وہ ملک بھر کے تمام اہل علم و دانش کو دعوت کے منصب سے معزول کرنے کا حکم کس بنیاد پر صادر کر رہے ہیں؟
پھر خورشید ندیم صاحب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ علماء کی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے ملک دستوری لحاظ سے اسلامی ہے اور قانون سازی میں یہ ضمانت موجود ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ ہمارے خیال میں اس معاملے کو ایک اور رخ سے دیکھا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ عملی سیاست میں علماء کے فریق بننے کی وجہ سے پاکستان اب تک سیکولر ریاست بننے سے بچا ہے۔ ورنہ اگر پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ موجود نہ ہوتے تو قرارداد مقاصد کبھی منظور نہ ہوتی۔ ۱۹۷۱ء کی دستور ساز اسمبلی میں مولانا مفتی محمودؒ ، مولانا عبد الحقؒ ، مولانا شاہ احمد نورانیؒ ، مولانا غلام غوث ہزارویؒ ، مولانا عبد المصطفیٰ ازہری، پروفیسر غفور احمد، اور مولانا ظفر احمد انصاری موجود نہ ہوتے تو اسلام کے سرکاری مذہب ہونے اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کی ضمانت جیسی بنیادی دفعات دستور کا حصہ نہیں بن سکتی تھیں۔ اور ۱۹۷۴ء میں یہی حضرات قومی اسمبلی کے رکن نہ ہوتے تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا تھا۔
لطف کی بات یہ ہے کہ خورشید احمد ندیم اس سارے کام کو مولانا ظفر احمد انصاری کے کھاتے میں ڈال کر انہیں عملی سیاست سے دور رہنے والا بزرگ قرار دے رہے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور کے دستور سازی کے عمل سے ہی سرے سے بے خبر ہیں۔ مولانا ظفر احمد انصاری کی خدمات اور کردار سے انکار نہیں، لیکن وہ دستور ساز اسمبلی اور قومی اسمبلی میں اس ٹیم کا ایک حصہ تھے جس میں مذکورہ بالا اکثر بزرگ شامل تھے اور ان کی قیادت مولانا مفتی محمودؒ کر رہے تھے۔ جبکہ عملی سیاست سے مولانا ظفر احمد انصاری کے دور رہنے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ۱۹۷۱ء کے الیکشن میں کراچی سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ کر دستور ساز اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے۔ اس لیے اگر وہ اس سارے انتخابی عمل سے گزر کر بھی عملی سیاست سے دور رہنے والے بزرگ قرار پا سکتے ہیں تو مذکورہ بالا دیگر بزرگوں کو یہ سہولت دینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
ہمارے خیال میں موجودہ عالمی حالات اور شدید بین الاقوامی دباؤ کے تناظر میں علماء کا پاکستان کو سیکولر ریاست بننے سے روکے رکھنا ہی ایک ایسی بنیادی کامیابی ہے جس کی خاطر عملی سیاست کے تمام مبینہ نقصانات برداشت کیے جا سکتے ہیں۔
مولانا زاہد الراشدی کی خدمت میں
معز امجد
پچھلے دنوں مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ایک مضمون ”غامدی صاحب کے ارشادات پر ایک نظر‘‘ تین قسطوں میں روزنامہ ”اوصاف‘‘ میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں مولانا محترم نے استاذِ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی بعض آرا پر اظہارِ خیال فرمایا ہے۔ مذکورہ مضمون میں مولانا محترم کے ارشادات سے اگرچہ ہمیں اتفاق نہیں ہے، تاہم ان کی یہ تحریر علمی اختلافات کے بیان اور مخالف نقطہء نظر کی علمی آرا پر تنقید کے حوالے سے ایک بہترین تحریر ہے۔ مولانا محترم نے اپنی بات کو جس سلیقے سے بیان فرمایا اور ہمارے نقطہء نظر پر جس علمی اندازسے تنقید کی ہے، وہ یقیناًموجودہ دور کے علما اور مفتیوں کے لیے ایک قابلِ تقلید نمونہ ہے۔ مولانا محترم کے اندازِ بیان اور ان کی تنقید کے اسلوب سے جہاں ہمارے دل میں ان کے احترام میں اضافہ ہوا ہے، وہیں اس سے ہمیں اپنی بات کی وضاحت اور مولانا محترم کے فرمودات کا جائزہ لینے کا حوصلہ بھی ملا ہے۔ اس مضمون میں ہم مولانا محترم کے اٹھائے ہوئے نکات کا بالترتیب جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور غلط باتوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔
علماے دین اور سیاست
سب سے پہلی بات، جس پر مولانا محترم نے تنقید کی ہے، وہ علماے دین کے کام کے حوالے سے استاذِ گرامی کی رائے ہے۔ مولانا محترم کے اپنے الفاظ میں، وہ اس طرح سے ہے:
’’علماے کرام خود سیاسی فریق بننے کی بجائے، حکمرانوں اور سیاست دانوں کی اصلاح کریں تو بہتر ہو گا، مولوی کو سیاست دان بنانے کے بجائے، سیاست دان کو مولوی بنانے کی کوشش کی جائے۔‘‘
مولانا محترم استاذِ گرامی کی اس رائے کے بارے میں لکھتے ہیں:
’’جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ علماے کرام خود سیاسی فریق بننے کی بجائے، حکمرانوں اور سیاست دانوں کی اصلاح کریں، تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ یہ موقع ومحل اور حالات کی مناسبت کی بات ہے اور دونوں طرف اہلِ علم اور اہلِ دین کا اسوہ موجود ہے۔ امت میں اکابر اہلِ علم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے حکمرانوں کے خلاف سیاسی فریق بننے کی بجائے ان کی اصلاح اور رہنمائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن ایسے اہلِ علم بھی امت میں رہے ہیں، جنھوں نے اصلاح کے دوسرے طریقوں کو کامیاب نہ ہوتا دیکھ کرخود فریق بننے کا راستہ اختیار کیا ہے ... اس لیے اگر کسی دور میں علماے کرام یہ سمجھیں کہ خود فریق بنے بغیر معاملات کی درستی کا امکان کم ہے تو اس کا راستہ بھی موجود ہے اور اس کی مطلقاً نفی کر دینا دین کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔‘‘
ہمیں مولانا محترم کی محولہ عبارت سے بہت حد تک اتفاق ہے۔ علماے دین کا سیاسی اکھاڑوں میں اترنے کا مسئلہ، جیسا کہ استاذِ گرامی کے رپورٹ کیے گئے بیان سے بھی واضح ہے، حرمت و حلت کا مسئلہ نہیں ہے۔ استاذِ گرامی کا نقطہء نظر یہ نہیں ہے کہ علما کا سیاست کے میدان میں اترنا حرام ہے، اس کے برعکس، ان کی رائے یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں اترنے کے بجائے، یہ ’بہتر ہوگا‘ کہ علماسیاست دانوں کی اصلاح کریں۔ ظاہر ہے کہ مسئلہ بہتر اور کہتر تدبیر کا ہے، نہ کہ حلال و حرام یا مطلقاً نفی کا۔
یہاں ہم البتہ، یہ بات ضرور واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآنِ مجید میں علماے دین کی جو ذمہ داری بیان ہوئی ہے، وہ اپنی قوم میں آخرت کی منادی کرنا اور اس کے بارے میں اپنی قوم کو انذار کرنا ہے۔ چنانچہ، اپنے کام کے حوالے سے وہ جو رائے بھی قائم کریں اور جس میدان میں اترنے کا بھی وہ فیصلہ کریں، انھیں یہ بات کسی حال میں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ سب سے پہلے اسی ذمہ داری کے حوالے سے مسؤل ٹھیریں گے جو کتابِ عزیز نے ان پر عائد کی ہے۔ اس وجہ سے انھیں اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ان کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے میں رکاوٹ تو نہیں بن جائے گا۔
ہم یہاں اتنی بات کا اضافہ ضروری سمجھتے ہیں کہ علماے کرام پر قرآنِ مجید نے اصلاحِ احوال کی نہیں، بلکہ اصلاحِ احوال کی جدوجہد کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ مولانا محترم اگر غور فرمائیں، تو ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ پہلی صورت میں منزلِ مقصود اصلاحِ احوال، جبکہ دوسری صورت میں اصلاح کی جدوجہد ہی راستہ اور اس راستے کا سفر ہی اصل منزل ہے۔ چنانچہ، ہمارے نزدیک، معاملات کی درستی کے امکانات خواہ بظاہر ناپید ہی کیوں نہ ہوں، علماے دین کا کام کامیابی کے امکانات کا جائزہ لینا نہیں، بلکہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داری کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرتے چلے جانا ہے۔ اس معاملے میں قرآنِ مجید نے ان لوگوں کا بطورِ مثال، خاص طور پر ذکر کیا ہے، جو یہود کی ایک بستی میں آخرت کی منادی کرتے تھے۔ یہ یہود کی اخلاقی پستی کا وہ دور تھا کہ اصلاح کی اس جدوجہد کی کامیابی کا سرے سے کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ، جب بستی والوں نے ان مصلحین سے یہ پوچھا کہ ناامیدی کی اس تاریکی میں وہ یہ کام آخر کس لیے کر تے چلے جا رہے ہیں، تو انھوں نے جواب دیا:
مَعْذِرَۃً اِلٰی رَبِّکُمْ۔ (الاعراف ۷: ۱۶۴)
’’اس لیے کہ تمھارے رب کے حضور یہ ہمارے لیے عذر بن سکے(کہ ہم نے اپنے کام میں کوئی کمی نہیں کی)۔‘‘
قرآنِ مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و انذار کے معاملے میں انبیاے کرام کا اسوہ بھی یہی رہا ہے۔ حالات کی نامساعدت اور کامیابی کی امید کے فقدان کو انھوں نے اپنے لیے کبھی رکاوٹ نہیں سمجھا۔ وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے تک اسی کام پر لگے رہے جس کا پروردگارِ عالم نے انھیں حکم دیا تھا۔ اس میدانِ عمل کا اسوۂ حسنہ یہی ہے۔ اس کی راہ پر چل نکلنا ہی منزل اور اس راہ میں اٹھایا ہوا ہر قدم ہی اصل کامیابی ہے۔
زکوٰۃ اور ٹیکس
اخبار کے بیان کے مطابق، استاذِگرامی نے کہا ہے:
’’زکوٰۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹیکسیشن کو ممنوع قرار دے کر حکمرانوں سے ظلم کا ہتھیار چھین لیا ہے۔‘‘
مولانا محترم اس بیان کے بارے میں لکھتے ہیں:
’’... لیکن کیا کسی ضرورت کے موقع پر (زکوٰۃ کے علاوہ) اور کوئی ٹیکس لگانے کی شرعاً ممانعت ہے؟ اس میں ہمیں اشکال ہے۔ اگر غامدی صاحب محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کے بعد کسی اور ٹیکسیشن کی ممانعت پر کوئی دلیل پیش فرما دیں، تو ان کی مہربانی ہو گی اور اس باب میں ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔‘‘
استاذِ گرامی اپنی بہت سی تحریروں میں اپنی رائے کی بنیاد واضح کر چکے ہیں۔ اپنے مضمون ’قانونِ معیشت‘ میں وہ لکھتے ہیں:
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلوٰۃَ وَاٰتَوُا الزَّکٰوۃَ فَخَلُّوْا سَبِیْلَھُمْ۔ (التوبۃ ۹: ۵)
’’پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔‘‘
سورۂ توبہ میں یہ آیت مشرکینِ عرب کے سامنے ان شرائط کی وضاحت کے لیے آئی ہے جنھیں پورا کر دینے کے بعد وہ مسلمانوں کی حیثیت سے اسلامی ریاست کے شہری بن سکتے ہیں۔ اس میں ’فخلوا سبیلہم‘ (ان کی راہ چھوڑ دو) کے الفاظ اگر غور کیجیے تو پوری صراحت کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آیت میں بیان کی گئی شرائط پوری کرنے کے بعد جو لوگ بھی اسلامی ریاست کی شہریت اختیار کریں، اس ریاست کا نظام جس طرح ان کی جان، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کوئی تعدی نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کی املاک، جائدادوں اور اموال کے خلاف بھی کسی تعدی کا حق اس کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اگر اسلام کے ماننے والے ہیں، نماز پر قائم ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں تو عالم کے پروردگار کا حکم یہی ہے کہ اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمانِ واجب الاذعان کی رو سے ایک مٹھی بھر گندم، ایک بالشت زمین، ایک پیسا، ایک حبہ بھی کوئی ریاست اگر چاہے تو ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لینے کے بعد بالجبر ان سے نہیں لے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے:
امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا عصموا منی وماء ہم واموالہم الا بحقہا وحسابہم علی اللہ۔ (مسلم، کتاب الایمان)
’’مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروںیہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ شرائط پوری کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے اموال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس سے محروم کر دیے جائیں۔ رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔‘‘
یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نہایت بلیغ اسلوب میں اس طرح بیان فرمائی ہے:
ان دماء کم واموالکم حرام علیکم لحرمۃ یومکم ھذا فی شھرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ (مسلم، کتاب الحج)
’’بے شک، تمھارے خون اور تمھارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں،(۱) جس طرح تمھارا یہ دن (یوم النحر) تمھارے اس مہینے (ذوالحجہ) اور تمھارے اس شہر (ام القری مکہ) میں۔‘‘
اس سے واضح ہے کہ اس آیت کی رو سے اسلامی ریاست زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے، اپنے مسلمان شہریوں پر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد قضیت ما علیک۔ (ترمذی، کتاب الزکوٰۃ)
’’جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تو وہ ذمہ داری پوری کر دیتے ہو جو (ریاست کی طرف سے) تم پر عائد ہوتی ہے۔‘‘
اسی طرح آپ نے فرمایا ہے:
لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ۔ (ابنِ ماجہ، کتاب الزکوٰۃ)
’’لوگوں کے مال میں زکوٰۃ کے سوا (حکومت کا) کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔‘‘
اربابِ اقتدار اگر اپنی قوت کے بل بوتے پر اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ ایک بد ترین معصیت ہے جس کا ارتکاب کوئی ریاست اپنے شہریوں کے خلاف کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
لا یدخل الجنۃ صاحب مکس۔ (ابو داؤد، کتاب الخراج والامارۃ والفء)
’’کوئی ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو گا۔‘‘
اسلام کا یہی حکم ہے جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف یہ کہ عوام اور حکومت کے مابین مالی معاملات سے متعلق ہر کشمکش کا خاتمہ کرتا، بلکہ حکومتوں کے لیے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلا کر قومی معیشت میں عدمِ توازن پیدا کردینے کا ہر امکان بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔
تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مال سے متعلق اللہ پروردگارِ عالم کے مطالبات بھی اس پر ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں تصریح ہے کہ اس معاملے میں اصل مطالبہ انفاق کا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا ہے کہ مال میں زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد حکومت کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے:
ان فی المال حقاً سوی الزکوٰۃ۔ (ترمذی، کتاب الزکوٰۃ)
’’بے شک، مال میں زکوٰۃ کے بعد بھی (اللہ کا) ایک حق قائم رہتا ہے۔‘‘
(ماہنامہ ”اشراق“، اکتوبر ۱۹۹۸، ص۲۹۔ ۳۲)
امید ہے کہ دیے گئے اقتباس سے مولانا محترم پر استاذِ گرامی کا استدلال پوری طرح سے واضح ہو جائے گا۔ مولانا محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس استدلال میں اگر کوئی خامی دیکھیں، تو ہمیں اس سے ضرور آگاہ فرمائیں۔
جہاد اور مسلمانوں کا نظمِ اجتماعی
اخبار کے بیان کے مطابق، استاذِ محترم نے کہا ہے:
’’جہاد تبھی جہاد ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی حکومت اس کا اعلان کرے۔ مختلف مذہبی گروہوں اور جتھوں کے جہاد کو جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔‘‘
مولانا محترم، استاذِگرامی کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’... جہاد کی مختلف عملی صورتیں اور درجات ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ملک یا قوم کے خلاف جہاد کا اعلان اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک اسلامی یا کم از کم مسلمان حکومت اس کا اعلان کرے، لیکن جب کسی مسلم آبادی پر کفار کی یلغار ہو جائے اور کفار کے غلبے کی وجہ سے مسلمان حکومت کا وجود ختم ہو جائے یا وہ بالکل بے بس دکھائی دینے لگے، تو غاصب اور حملہ آور حکومت کے خلاف جہاد کے اعلان کے لیے پہلے حکومت کا قیام ضروری نہیں ہو گا اور نہ ہی عملاً ایسا ممکن ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسے مرحلہ میں مسلمانوں کی اپنی حکومت کا قیام قابلِ عمل ہو تو کافروں کی یلغار اور تسلط ہی بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ صورت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں کی حکومت کفار کے غلبہ اور تسلط کی وجہ سے ختم ہو جائے، بے بس ہو جائے یا اسی کافر حکومت کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن کر رہ جائے۔
سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے گا؟ اگر جاوید غامدی صاحب محترم کا فلسفہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ ضروری ہو گا کہ مسلمان پہلے اپنی حکومت قائم کریں اور اس کے بعد اس حکومت کے اعلان پر جہاد شروع کیا جائے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہو گا کہ جب مسلمانوں نے اپنی حکومت بحال کر لی ہے تو اب جہاد کے اعلان کی ضرورت ہی کیا باقی رہ گئی ہے؟ کیونکہ جہاد کا مقصد تو کافروں کا تسلط ختم کر کے مسلمانوں کا اقتدار بحال کرنا ہے اور جب وہ کام جہاد کے بغیر ہی ہو گیا ہے تو جہاد کے اعلان کا کون سا جواز باقی رہ جاتا ہے؟‘‘
مولانا محترم کی یہ بات کہ کسی قوم یا ملک کے خلاف جہاد تو بہرحال مسلمان حکومت ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے باعثِ صد مسرت ہے۔ ہم اسے بھی غنیمت سمجھتے ہیں کہ موحودہ حالات میں مولانا نے اس حد تک تو تسلیم کیا کہ کسی ملک وقوم کے خلاف جہاد مسلمان حکومت ہی کر سکتی ہے۔ چنانچہ اب ہمارے اور مولانا کے درمیان اختلاف صرف اسی مسئلے میں ہے کہ اگر کبھی مسلمانوں پر کوئی بیرونی قوت اس طرح سے تسلط حاصل کر لے کہ مسلمانوں کا نظمِ اجتماعی اس کے آگے بالکل بے بس ہو جائے تو اس صورت میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ واضح رہے کہ ایسے حالات میں مولانا ہی کی بات سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ بیرونی طاقت کے خلاف اگر مسلمانوں کا نظمِ اجتماعی اپنی سلطنت کے دفاع کا انتظام کرنے کو آمادہ ہو تو اس صورت میں بھی مسلمانوں کے نظمِ اجتماعی ہی کی طرف سے کی جانے والی جدوجہد ہی اس بات کی مستحق ہو گی کہ اسے جہاد قرار دیا جائے۔ مزید برآں ایسے حالات میں نظمِ اجتماعی سے ہٹ کر، جتھہ بندی کی صورت میں کی جانے والی ہر جدوجہد، غلط قرار پائے گی۔ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ مولانا کو ہماری اس بات سے اتفاق ہو گا، تاہم پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ مولانا ہمارے اس خیال کی تصدیق یا تردید ضرور فرما دیں، تاکہ اس معاملے میں قارئین کے ذہن میں بھی کوئی شک باقی نہ رہے۔ چنانچہ ہمارے فہم کی حد تک، اب ہمارے اور مولانا کے درمیان اختلاف صرف اس صورت سے متعلق ہے جب مسلمانوں کا نظمِ اجتماعی، کسی بھی وجہ سے، بیرونی طاقت کے تسلط کے خلاف جدوجہد کرنے سے قاصر ہو۔ مولانا کے نزدیک اس صورت میں مسلمانوں کو ہر حال میں اپنی سلطنت کے دفاع کی جدوجہد کرنی چاہیے، خواہ یہ جدوجہد غیر منظم جتھہ بندی ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ مزید یہ کہ اس ضمن میں جو منظم یا غیر منظم جدوجہد بھی مسلمانوں کی طرف سے کی جائے گی، وہ مولانا محترم کے نزدیک ’جہاد ‘ہی قرار پائے گی۔
مولانا محترم نے اپنی بات کی وضاحت میں فلسطین، برِ صغیر پاک وہند، افغانستان اور الجزائرکی کامیاب جدوجہدِ آزادی اور دمشق کے عوام میں تاتاریوں کے خلاف کامیابی کے ساتھ جہاد کی روح پھونکنے کے معاملے میں ابنِ تیمیہ رحمہ اللہ کی کوششوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم اپنا نقطہء نظر بیان کرنے سے پہلے، تین باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں: اول یہ کہ مولانا محترم نے جتنے واقعات کا حوالہ دیا ہے، ان سب کی مولانا محترم کی رائے سے مختلف توجیہ نہ صرف یہ کہ کی جا سکتی بلکہ کی گئی ہے۔ دوم یہ کہ کسی جدوجہد کی اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی، اس جدوجہد کے شریعتِ اسلامی کے مطابق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی اور نہ کسی جدوجہد کی اپنے مقصد کے حصول میں ناکامی اس کے خلافِ شریعت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور سوم یہ کہ عام انسانوں کی بات بے شک مختلف ہو گی، مگر مولانا محترم جیسے اہلِ علم سے ہماری توقع یہی ہے کہ وہ اہلِ علم کے عمل سے شریعت اخذ کرنے کے بجائے، شریعت کی روشنی میں اس عمل کا جائزہ لیں۔ اگر شریعتِ اسلامی کے بنیادی ماخذوں، یعنی قرآن و سنت، میں اس عمل کی بنیاد موجود ہے تو اسے شریعت کے مطابق اور اگر ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو بغیر کسی تردد کے اسے شریعت سے ہٹا ہوا قرار دیں۔ ’جہاد‘ یا ’قتال‘ شریعتِ اسلامی کی اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات کی تعریف یا ان کے بارے میں تفصیلی قانون سازی کا ماخذ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کا اسوہ اور ان کی جاری کردہ سنت ہی ہو سکتی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی جدوجہد ہو یا برِ صغیر پاک و ہند، افغانستان، الجزائریا دمشق کے مسلمانوں کی، یہ جدوجہد جہاد و قتال کی تعریف اور قانون سازی کا ماخذ نہیں، بلکہ خود اس بات کی محتاج ہے کہ شریعت کے بنیادی ماخذوں کی روشنی میں اس کی صحت یا عدمِ صحت کا فیصلہ کیا جائے۔ مولانا یقیناًاس بات سے اتفاق کریں گے کہ شریعتِ اسلامی مسلمانوں کے عمل سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عمل شریعتِ اسلامی سے ماخوذ ہوناچاہیے۔ وہ یقیناًاس بات کو تسلیم کریں گے کہ شریعتِ اسلامی کے فہم کی اہمیت اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے ہر قسم کے جذبات و تعصبات سے بالا ہو کر پوری دیانت داری کے ساتھ پہلے سمجھ لیا جائے اور پھر پورے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ جذبات و تعصبات سے الگ ہو کر غور کرنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بات کو اصولی سطح پر سمجھ لیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر ضروری محسوس ہو تو فلسطین، برصغیر پاک و ہند، افغانستان، الجزائر اور دمشق کے مسلمانوں کی جدوجہد کو شریعت سے مستنبط اصولی رہنمائی کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔
اس وضاحت کے بعد، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآنِ مجید اور اس کے پیغمبروں کا اسوہ اور ان کی جاری کردہ سنت زیرِ غور مسئلے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں:
سب سے پہلی صورت جو ہمارے اور مولانا محترم کے درمیان متفق علیہ ہے، یہ ہے کہ کسی قوم و ملک کے خلاف جارحانہ اقدام اسی صورت میں ’جہاد‘ کہلانے کا مستحق ہو گا، جب یہ مسلمانوں کی کسی حکومت کی طرف سے ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی منظم حکومت کی طرف سے ہونا، اس اقدام کے جواز کی شرائط میں سے ایک شرط ہی ہے۔ بات یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی منظم حکومت کی طرف سے کیا گیا ہر اقدام ’جہاد‘ ہی ہوتا ہے، بلکہ یوں ہے کہ ’جہاد‘ صرف مسلمانوں کی منظم حکومت ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔
دوسری صورت، جس کا اگرچہ مولانا محترم نے اپنی تحریر میں ذکر تو نہیں کیا، تاہم ان کی باتوں سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان ریاست کے خلاف جارحانہ اقدام کیا جائے اور اس کا نظمِ اجتماعی اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو اور اس مقصد کے لیے جارح قوم کے خلاف میدانِ جنگ میں اترے، تو اس صورت میں بھی مسلمانوں کی منظم حکومت ہی کی طرف سے کیا گیا اقدام ’جہاد‘ کہلانے کا مستحق ہو گا۔ اس صورت میں تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہو گا کہ وہ اپنے نظمِ اجتماعی ہی کے تحت منظم طریقے سے اپنے ملک و قوم کا دفاع کریں اور اس سے الگ ہو کر کسی خلفشار کا باعث نہ بنیں۔ یہ صورت، اگر غور کیجیے، تو پہلی صورت ہی کی ایک فرع ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاملہ خواہ قوم کے دفاع کا ہویا کسی جائز مقصد سے کسی دوسری قوم کے خلاف جارحانہ اقدام کا، دونوں ہی صورتوں میں یہ چونکہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے متعلق ہے، لہٰذا اس کے انتظام کی ذمہ داری اصلاً ان کی اجتماعیت ہی پر ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر عام مسلمانوں کو دین و شریعت کی ہدایت یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے پیش کر دیں، اپنے حکمرانوں (اولوالامر) کی اطاعت کریں اور ہر حال میں اپنے نظمِ اجتماعی (الجماعۃ) کے ساتھ منسلک رہیں۔ ان کا نظمِ اجتماعی انھیں جس محاذ پر فائز کرے، وہ وہیں سینہ سپر ہوں، ان کا نظمِ اجتماعی جب انھیں پیش قدمی کا حکم دے تو اسی موقع پر وہ پیش قدمی کریں اور اگر کبھی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا اجتماعی نظم انھیں دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دینے کا حکم دے، تو وہ اپنے ملک و قوم ہی کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے، اس ذلت کو بھی برداشت کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔
منظم اجتماعی دفاع و اقدام کی ان دو واضح صورتوں کے علاوہ اندرونی یا بیرونی قوتوں کے جبر و استبداد کی بہت سی دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اور مولانا محترم کے درمیان اختلاف اصلاً انھی دوسری صورتوں سے متعلق ہے۔ مولانا محترم کے نزدیک، اوپر دی ہوئی دونوں صورتوں کو چھوڑ کر، جبر و استبداد کی باقی صورتوں میں مسلمانوں کو گروہوں، جتھوں اور ٹولوں کی صورت میں اپنا دفاع اور آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیے اور اس صورتِ حال میں یہی جدوجہد ’جہاد‘ قرار پائے گی۔ ہمارے نزدیک، مولانا محترم کی یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک، ایسی صورتِ حال میں بھی دین و شریعت کی ہدایت وہی ہے، جو پہلی دو صورتوں میں ہمارے اور مولانا محترم کے درمیان متفق علیہ ہے۔ شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہو گا کہ دین و شریعت کی رو سے جہاد و قتال کی غیر منظم جدوجہد، بالعموم، جن ہمہ گیر اخلاقی و اجتماعی خرابیوں کو جنم دیتی ہے، شریعتِ اسلامی انھیں کسی بڑی سے بڑی منفعت کے عوض بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اور انبیاے کرام کی معلوم تاریخ سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جبر و استبداد کی قوتوں کے خلاف، خواہ یہ قوتیں اندرونی ہوں یا بیرونی، اسی صورت میں تلوار اٹھانے کا حکم اور اس کی اجازت دی، جب مسلمان اپنی ایک خودمختار ریاست قائم کر چکے تھے۔ اس سے پہلے کسی صورت میں بھی انبیاے کرام کو کسی جابرانہ تسلط کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔
جابرانہ تسلط میں حالات کی رعایت سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ درجِ ذیل ہیں:
۱۔ جہاں محکوم قوم کو اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی حاصل ہو۔
۲۔ جہاں محکوم قوم کو اپنے مذہب و عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت حاصل نہ ہو۔
پہلی صورت میں جابرانہ تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا ہر محکوم قوم کا حق تو بے شک ہے، مگر یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی اصول پر حضرتِ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے موقع پر اگرچہ بنی اسرائیل رومی سلطنت کے محکوم ہو چکے تھے، تاہم اللہ کے اس پیغمبر نے انھیں نہ کبھی رومی تسلط کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرنے کا مشورہ دیا اور نہ خود ہی ایسی کسی جدوجہد کی بنا ڈالی۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسے حالات میں آزادی کی جدوجہد کو دین میں مطلوب و مقصود کی حیثیت حاصل ہوتی، تو حضرتِ مسیح جیسے اولو العزم پیغمبر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ دین کے اس مطلوب و مقصود سے گریز کی راہ اختیار کرتے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی صورتِ حال میں آزادی کی جدوجہد دین و شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس بات سے بہرحال اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی صورتِ حال میں بھی آزادی کی جدوجہد ہر قوم کا فطری حق ہے۔ وہ یقیناًیہ حق رکھتی ہے کہ اس جابرانہ تسلط سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد کرے۔ مگر چونکہ یہ جدوجہد دین کا تقاضا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اسے نہ صرف پرامن بنیادوں ہی پر استوار کیا جائے، بلکہ اس بات کا بھی پوری طرح سے اہتمام کیا جائے کہ مسلمانوں کے کسی اقدام کی وجہ سے کسی مسلم یا غیر مسلم کا خون نہ بہنے پائے۔ اس جدوجہد میں مسلمانوں کے رہنماؤں کو یہ بات بہرحال فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دین و شریعت میں جان و مال کی حرمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ انھیں ہر حال میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے کسی اقدام کے نتیجے میں جان و مال کی یہ حرمت اگر ناحق پامال ہوئی، تو اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ اپنے اس اقدام کے لیے اللہ کے حضور میں مسؤل قرار پا جائیں۔ جان و مال کی یہ حرمت اگر کسی فرد یا قوم کے معاملے میں ختم ہو سکتی ہے تو شریعت ہی کی دی ہوئی رہنمائی میں ختم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ، ظاہر ہے کہ جبر و تسلط کی اس پہلی صورت میں اگر آزادی کی جدوجہد دین و شریعت کا تقاضا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیے گئے کسی جارحانہ اقدام کو نہ ’جہاد‘ قرار دیا جا سکتا اور نہ اس راہ میں لی گئی کسی جان کو جائز ہی ٹھیرایا جا سکتا ہے۔
دوسری صورت وہ ہے کہ جب کسی دوسری قوم پر جابرانہ تسلط ایسی صورت اختیار کر لے کہ محکوم قوم کے باشندوں کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت حاصل نہ ہو۔ اس صورت میں محکوم قوم کے امکانات کے لحاظ سے دو ضمنی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں:
۱۔ جہاں محکوم قوم کے لیے جابرانہ تسلط کے علاقے سے ہجرت کر جانے کی راہ موجود ہو۔
۲۔ جہاں محکوم قوم کے لیے ہجرت کی راہ مسدود ہو۔
اگر مذہبی جبر اور استبداد کے دور میں لوگوں کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کر جانے اور کسی دوسرے علاقے میں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی راہ کھلی ہو، تو اس صورت میں دین کا حکم یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی خاطر، اپنے ملک اور اپنی قوم کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ قرآنِ مجید کے مطابق ایسے حالات میں ہجرت نہ کرنا اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو مذہبی جبر اور استبداد کا نشانہ بنے رہنے دینا جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفّٰھُمُ الْمَآءِکَۃُ ظَالِمِیْٓ اَنْفُسِھِمْ قَالُوْ فِیْمَ کُنْتُمْ، قَالُوْا کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْاَرْضِ قَالُوْآ اَلَمْ تَکُنْ اَرْضُ اللّٰہِ وَاسِعَۃً فَتُہَا جِرُوْا فِیْھَا فَاُولٰٓءِکَ مَاْوٰھُمْ جَھَنَّمُ وَسَآءَ تْ مَصِیْرًا۔ (النساء ۴: ۹۷)
’’بے شک، جن لوگوں کو فرشتے اس حال میں موت دیں گے کہ وہ (ظلم و جبر کے باوجود یہیں بیٹھے) اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو وہ ان سے پوچھیں گے: ’تم کہاں پڑے رہے؟‘ وہ کہیں گے: ’ہم اپنی زمین میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے‘۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے: ’کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہ تھی کی تم اس میں (کہیں اور) ہجرت کر جاتے؟‘ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہو گا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔‘‘
ہجرت کی یہی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں پیش آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہجرت مصر سے صحراے سینا کی طرف تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے یثرب کو مدینۃ النبی بننے کا شرف بخشا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس ہجرت سے پہلے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں نثار ساتھیوں کو جبر وا ستبداد کے خلاف کسی جہاد کے لیے منظم کیا اور نہ حضرت موسیٰ ہی نے اس طرح کی کسی جہادی کارروائی کی روح اپنی قوم میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر پیغمبروں کا اسوہ یہی ہے کہ ظلم و استبداد کی بدترین تاریکیوں میں بھی انھوں نے فدائین کے جتھے، گروہ اور ٹولے تشکیل دینے کے بجائے، صبر واستقامت سے دار الہجرت کے میسر آنے کا انتظار کیا اور اس وقت تک ظلم و جبر کے خاتمے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جب تک اللہ کی زمین پر انھیں ایک خود مختار ریاست کا اقتدار نہیں مل گیا۔
اس کے برعکس، اگر ایسے حالات میں دارالہجرت میسر نہ ہو یا کسی اور وجہ سے ہجرت کرنے کی راہیں مسدود ہوں، تو اس صورت میں بھی قرآنِ مجید میں دو امکانات بیان ہوئے ہیں: اولاًیہ کہ ان حالات میں ظلم و استبداد کا نشانہ بنے ہوئے یہ لوگ کسی منظم اسلامی ریاست کو اپنی مدد کے لیے پکاریں۔ ایسے حالات میں قرآنِ مجید نے اس اسلامی ریاست کو، جسے لوگ مدد کے لیے پکاریں، یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس کے لیے اس جابرانہ اور استبدادی حکومت کے خلاف ان مسلمانوں کی مدد کرنی ممکن ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ یہ مدد کرے، الا یہ کہ جس قوم کے خلاف اسے مدد کرنے کے لیے پکارا جا رہا ہے، اس کے اور مسلمانوں کی اس ریاست کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ موجود ہو۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُہَاجِرُوْا مَا لَکُمْ مِّنْ وَّلَایَتِہِمْ مِّنْ شَیْ ءٍ حَتّٰی یُھَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰی قوَمٍْ م بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَھُمْ مِّیْثَاقٌ وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ۔ (الانفال ۸: ۷۲)
’’وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مگر جنھوں نے ہجرت نہیں کی، تم پر ان کی اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے تمھارے پاس نہ آ جائیں۔ البتہ، وہ اگر تمھیں دین کے نام پر مدد کے لیے پکاریں، تو تم پر ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری ہے، الا یہ کہ جس قوم کے خلاف وہ تمھیں مدد کے لیے پکاریں، اس کے اور تمھارے درمیان کوئی معاہدہ موجود ہو۔ اور یاد رکھو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔‘‘
پھر ایک اور مقام پر وقت کی اسلامی ریاست کو ان مجبور مسلمانوں کی مدد پر ابھارتے ہوئے فرمایا:
وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَالْمُسْتَضْعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ ھٰذِہِ الْقَرْیَۃِ الظَّالِمِ اَھْلُھَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیّاً وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ نَصِیْرًا۔ (النساء ۴: ۷۵)
’’اور تمھیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس ظالم باشندوں کی بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار کھڑے کر۔‘‘
ثانیاً یہ کہ ظلم و استبداد کے ان حالات میں ان کے لیے مسلمانوں کی کسی منظم ریاست سے مدد طلب کرنے یا کسی ریاست کے ان کی مدد کو آنے کا امکان موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لوگ صبر و استقامت کے ساتھ ان حالات کو برداشت کریں، یہاں تک کہ آں سوے افلاک سے ان کی آزمایش کے خاتمے کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ قرآنِ مجید میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے ان کے حوالے سے فرمایا ہے:
وَاِنْ کَانَ طَآءِفَۃٌ مِّنْکُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِیْٓ اُرْسِلْتُ بِہٖ وَطَآءِفَۃٌ لَّمْ یُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰی یَحْکُمَ اللّٰہُ بَیْنَنَا وَ ھُوَ خَیْرُ الْحٰکِمِیْنَ۔ (الاعراف ۷: ۸۷)
’’اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس بات پر ایمان لے آئے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور ایک گروہ اسے ماننے سے انکار کرے، تو (ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ) وہ صبر کریں، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اور یقیناً اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔‘‘
مولانا حمید الدین فراہی اسی صورتِ حال کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’... اپنے ملک کے اندر بغیر ہجرت کے جہاد جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت اور ہجرت سے متعلق دوسری آیات سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اگر صاحبِ جمیعت اور صاحبِ اقتدار امیر کی طرف سے نہ ہو تو وہ محض شورش و بد امنی اور فتنہ و فساد ہے۔‘‘ (مجموعہء تفاسیرِ فراہی، ص۵۶)
قرآنِ مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاے کرام کے حوالے سے، ظلم و استبداد کی مذکورہ صورتیں اور ان صورتوں کا مقابلہ کرنے میں اللہ کے ان جلیل القدر پیغمبروں کا اسوہ بیان ہوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مولانا محترم پیغمبروں کے اس اسوہ سے جہاد و قتال کے احکام کا استنباط کرنے کے بجائے، مسلمان قوموں کی تحریک ہاے آزادی ہی سے جہاد کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام اخذ کرنے پر کیوں مصر ہیں۔ ہم البتہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب کبھی غیر مقتدر گروہوں کی طرف سے تلوار اٹھائی گئی ہے، تو اس اقدام نے آزادی کی تحریک کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو یا نہ پہنچایا ہو، ظلم و جبر کی قوتوں کو بے گناہ شہریوں، عورتوں اور بچوں پر ظلم و جبر کے مزید پہاڑ گرانے کا جواز ضرور فراہم کیا ہے۔ لوگ خواہ اس قسم کی قتل و غارت کو جبر و استبداد کی بڑھتی ہوئی لہریں قرار دے کر اپنے دلوں کو کتنی ہی تسلی دیتے رہیں، ہمیں یہ بات بہرحال فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دین و شریعت سے اعراض کر کے، اپنی بے تدبیری اور بے حکمتی کے ساتھ امن و امان کی فضا خراب کر کے ظلم و جبر کو اخلاقی جواز فراہم کرنا، کسی حال میں بھی ظلم و جبر کا ساتھ دینے سے کم نہیں ہے۔
فتووں پر پابندی
اخبار کے بیان کے مطابق، استاذِگرامی نے کہا ہے:
’’فتووں کا بعض اوقات انتہائی غلط استعمال کیاجاتا ہے۔ اس لیے فتویٰ بازی کو اسلام کی روشنی میں ریاستی قوانین کے تابع بنانا چاہیے اور مولویوں اور فتووں کے خلاف بنگلہ دیش میں (عدالت کا) فیصلہ صدی کا بہترین فیصلہ ہے۔‘‘
مولانا محترم استاذِ گرامی کی اس رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’جہاں تک اس شکایت کا تعلق ہے کہ ہمارے ہاں بعض فتووں کا انتہائی غلط استعمال ہوتا ہے ہمیں اس سے اتفاق ہے۔ ان فتووں کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے غیر سرکاری سطح پر کوئی قابلِ عمل فارمولا سامنے آتا ہے تو ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہو گا۔ مگر کسی چیز کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سرے سے اس کے وجود کو ختم کر دینے کی تجویز ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ چونکہ ہماری عدالتوں میں رشوت اور سفارش اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اکثر فیصلے غلط ہونے لگے ہیں اور عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے ان عدالتوں میں بیٹھنے والے ججوں سے فیصلے دینے کا اختیار ہی واپس لے لیا جائے۔ یہ بات نظری طور پر تو کسی بحث و مباحثے کا خوب صورت عنوان بن سکتی ہے، مگر عملی میدان میں اسے بروے کار لانا کس طرح ممکن ہے؟...
اور ”فتویٰ“ تو کہتے ہی کسی مسئلے پر غیر سرکاری ”رائے“ کو ہیں کیونکہ کسی مسئلہ پر حکومت کا کوئی انتظامی افسر جو فیصلہ دے گا، وہ ”حکم“ کہلائے گااور عدالت فیصلہ صادر کرے گی تو اسے ”قضا“ کہا جائے گا اور ان دونوں سے ہٹ کر اگر کوئی صاحبِ علم کسی مسئلے کے بارے میں شرعی طور پر حتمی رائے دے گاتو وہ ”فتویٰ“ کہلائے گا۔ امت کا تعامل شروع سے اسی پر چلا آ رہا ہے کہ حکام حکم دیتے ہیں، قاضی حضرات عدالتی فیصلے دیتے ہیں اور علماے کرام فتوی صادر کرتے ہیں۔‘‘
ہم مولانا محترم کو یقین دلاتے ہیں کہ استاذِگرامی کی مذکورہ رائے بھی اسی قسم کے فتووں سے متعلق ہے، جسے مولانا محترم نے بھی ’فتووں کا انتہائی غلط استعمال‘ قرار دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مولانا محترم کسی نامعلوم وجہ سے اس ’انتہائی غلط استعمال‘ کی روک تھام کے لیے بھی کسی ’غیر سرکاری‘ فارمولے ہی کے قائل ہیں. جبکہ ہمارے استاذ کے نزدیک فتووں کا یہ ’انتہائی غلط استعمال‘ بالعموم، جن مزید ’انتہائی غلط‘ نتائج و عواقب کا باعث بنتا اور بن سکتا ہے، اس کے پیشِ نظراس کی روک تھام کے لیے سرکاری سطح پرسخت قانون سازی کرنا ضروری ہو گیا ہے۔
ہم یہاں یہ ضروری محسوس کرتے ہیں کہ قارئین پر صحیح اور غلط قسم کے فتووں کا فرق واضح کر دیں۔ اس کے بعد قارئین خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ دور کے علما میں فتووں کا صحیح اور ’انتہائی غلط‘ استعمال کس تناسب سے ہوتا ہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ علماے کرام کی سب سے بڑی اور اہم ترین ذمہ داری، عوام و خواص کے سامنے دینِ متین کی شرح و وضاحت کرنا اور مختلف صورتوں اور احوال کے لیے دین و شریعت کا فیصلہ ان کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ علما ہی کا کام ہے کہ وہ نکاح و طلاق کے بارے میں شریعت کے احکام کی وضاحت کریں، یہ انھی کا مقام ہے کہ وہ قتل و سرقہ، قذف و زنا اور ارتداد وغیرہ کے حوالے سے شریعت کے احکام بیان کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس طرح کے تمام احکام کی شرح و وضاحت کا کام علما ہی کو زیب دیتا ہے اور وہی اس کے کرنے کے اہل ہیں۔ علما کے اس کام پر پابندی لگانا تو درکنار، اس کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنا بھی بالکل ممنوع قرار پانا چاہیے۔ تاہم، ریاستی سطح پر قانون سازی اور اس قانون سازی کے مطابق مقدمات کے فیصلے کرنے کا معاملہ محض مختلف علما کے رائے دے دینے ہی سے پورا نہیں ہو جاتا۔ اس کے آگے بھی کچھ اہم مراحل ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں، سب سے پہلے ملک کی پارلیمان کو مختلف علما کی رائے سامنے رکھتے اور ان کے پیش کردہ دلائل کا جائزہ لیتے ہوئے، ملکی سطح پر قانون سازی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، ملکی سطح پر قانون سازی کرتے ہوئے تمام مکاتبِ فکر اور علما کی رائے کو سامنے تو رکھا جا سکتا ہے، مگر ان سب کی رائے کو مانا نہیں جاسکتا۔ رائے بہرحال وہی نافذالعمل ہوگی اور ملکی اور ریاستی قانون کا حصہ بنے گی، جو پارلیمان کے نمائندوں کے نزدیک زیادہ صائب اور قابلِ عمل سمجھی جائے گی۔ قانون سازی کے اس عمل کے بعد بھی علما کا یہ حق تو بے شک برقرار رہتا ہے کہ وہ قانون و اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی بات کو مزید واضح کرنے، اس کے حق میں مزید دلائل فراہم کرنے اور پارلیمان کے نمائندوں کو اس پر قائل کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں۔ لیکن ریاست کا نظم یہ تقاضا بہرحال کرتا ہے کہ اس میں جس رائے کے مطابق بھی قانون سازی کر دی گئی ہو، اس میں بسنے والے تمام لوگ عوام خواص اور علما اس قانون کا پوری طرح سے احترام کریں اور اس کے خلاف انارکی اور قانون شکنی کی فضا پیدا کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ پارلیمان کے اختیار کردہ قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش ہونے والے مقدمات کے فیصلے کرنے کا ہے۔ یہ مرحلہ، دراصل، قانون کے اطلاق کا مرحلہ ہے۔ اس میں عدالت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فریقین کی رائے سن کر، ملکی پارلیمان کی قانون سازی کی روشنی میں حق و انصاف پر مبنی فیصلہ صادر کرے۔
جن فتووں کو ہم ’انتہائی غلط‘ سمجھتے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو جن کے شر و فساد سے بچانے کے لیے قانون سازی کو نہ صرف جائز بلکہ بعض صورتوں میں ضروری سمجھتے ہیں، ان کا تعلق دراصل قانون سازی اور اس کے بعد کے مراحل سے ہے۔
چنانچہ، مثال کے طور پر، یہ بے شک علماے دین کا کام ہے کہ وہ دین و شریعت کے اپنے اپنے فہم کے مطابق لوگوں کو یہ بتائیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس میں غلطی کی صورت میں کون کون سے احکام مترتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی علما ہی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کے فہم کے مطابق کن کن صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی اور کن کن صورتوں میں اس کے وقوع کے خلاف فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ تاہم ریاستی سطح پر طلاق کے بارے میں قانون سازی، ہما شما کی رائے پر نہیں بلکہ پارلیمان کے نمائندوں کی اکثریت کے کسی ایک رائے کے قائل ہو جانے پر منحصر ہو گی۔ پارلیمان میں طے پا جانے والی یہ رائے بعض علما کی رائے کے خلاف تو ہو سکتی ہے، مگر ریاست میں واجب الاطاعت قانون کی حیثیت سے اسی کو نافذ کیا جائے گا اور، علما سمیت، تمام لوگوں پر اس کی پابندی کرنی لازم ہو گی۔ مزید برآں، یہ فیصلہ کہ زید یا بکر کے کسی خاص اقدام سے اس کی طلاق واقع ہو گئی یا اس کا نکاح فسخ ہو گیا ہے، ایک عدالتی فیصلہ ہے، جس کا دین کی شرح و وضاحت اور علماے کرام کے دائرہء کار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ فیصلے بھی علماے کرام ہی کو کرنے ہیں، تو پھر مولانا محترم ہی ہمیں سمجھا دیں کہ عدالتوں کے قیام اور ان میں مقدمات کو لانے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔
اسی طرح، یہ علماے دین ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے نقطہء نظر کے مطابق ارتداد کی صورتوں اور ان کی مجوزہ سزاؤں کو پارلیمان سے منوانے کی کوشش کریں۔ تاہم یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کے خلاف، پارلیمان کے نمائندوں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں۔ مزید برآں، کسی خاص شخص کو مرتد قرار دینا بھی، چونکہ قانون کے اطلاق ہی کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ بھی علما کے نہیں بلکہ عدالت کے دائرے کی بات ہے، جو اسے مقدمے کے گواہوں کے بیانات، ان پر جرح اور ملزم کو صفائی کا پورا پورا موقع دے دینے کے بعد انصاف کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی کرنا چاہیے۔ یہی معاملہ کسی فرد یا گروہ کو کافر یا واجب القتل قرار دینے اور اس سے ملتے جلتے معاملات کا ہے۔ چنانچہ، فتووں کے ’انتہائی غلط استعمال‘ ہی کی ایک مثال بنگلہ دیشی عدالت کا فیصلہ صادر ہونے کے بعد اگلے ہی روز سامنے آئی، جب بنگلہ دیشی علما کے ایک گروہ نے فیصلہ کرنے والے جج کو ’مرتد‘ اور، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں، واجب القتل قرار دے دیا۔ مولانا محترم ہی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اس قسم کے فتوے کو سن کر کوئی مذہبی انتہا پسند فیصلہ کرنے والے جج کو، صفائی کا موقع دیے یا اس کی بات کو سمجھے بغیراپنے طور پر خدا نخواستہ، قتل کر دے تو کیا ریاست کو ایسے انتہا پسندوں کے ساتھ ساتھ فتووں کا یہ ’انتہائی غلط استعمال‘ کرنے والے علما کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے؟ مولانا محترم کا جواب یقیناًنفی ہی میں ہو گا، کیونکہ اس معاملے میں ان کا ’فتویٰ‘ تو یہی ہے کہ فتووں کے اس ’انتہائی غلط استعمال‘ کی روک تھام کے لیے بھی اگر کوئی اقدام ہونا چاہیے، تو وہ ’غیر سرکاری سطح‘ ہی پر ہونا چاہیے۔
مولانا کی مذکورہ رائے کے برعکس، ہمارے نزدیک، فتووں کے اس طرح کے ’انتہائی غلط استعمال‘ کی روک تھام کے لیے ’سرکاری سطح پر‘ مناسب قانون سازی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔
اس ضمن میں علما صحابہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ انھیں تقسیمِ میراث کے معاملے میں عول و رد کے قانون سے اتفاق نہیں تھا۔ تاہم ان کا یہ اختلاف ہمیشہ جائز حدود کے اندر ہی رہا۔ وہ اپنے اس اختلاف کا ذکر اپنے شاگردوں میں تو کرتے تھے اور بے شک یہ ان کا فطری حق بھی تھا، مگر انھوں نے نہ اپنے اس اختلاف کی وجہ سے قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی، نہ اس کی بنیاد پر حکومت کے خلاف پراپگینڈہ کیا اور نہ ریاست میں تقسیمِ وراثت کے معاملے میں اپنے فتوے جاری کیے۔
علماے کرام کے فتوے بھی جب تک ان اخلاقی اور قانونی حدود کے اندر رہیں، اس وقت تک وہ یقیناًخیر و برکت ہی کا باعث بنیں گے۔ مگر ان حدود سے باہرپارلیمان اور عدالتوں کے کام میں مداخلت کرنے والے فتووں پر پابندی نہ صرف مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ منظم اجتماعی زندگی کی تشکیل کے لیے ناگزیر محسوس ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح باتوں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا فرمائے اور غلط باتوں کے شر سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں محفوظ و مامون رکھے۔
علماء کے سیاسی کردار پر جناب غامدی کا موقف
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
غالباً عید الفطر کے ایام کی بات ہے کہ محترم جاوید احمد غامدی نے پشاور پریس کلب میں جہاد، فتویٰ، زکوٰۃ، ٹیکس اور علماء کے سیاسی کردار کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو ملک کے جمہور علماء کے موقف اور طرز عمل سے مختلف تھے۔ اس لیے میں نے روزنامہ اوصاف اسلام آباد میں مسلسل شائع ہونے والے اپنے کالم ’’نوائے قلم‘‘ میں ان کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ اس پر غامدی صاحب محترم کے شاگرد رشید جناب خورشید احمد ندیم نے روزنامہ جنگ میں غامدی صاحب کے موقف کی مزید وضاحت کی جن پر میں نے ان کی چند باتوں پر روزنامہ اوصاف میں دوبارہ تبصرہ کر دیا۔
اس کے بعد غامدی صاحب کے ایک اور شاگرد معز امجد نے روزنامہ پاکستان میں انہی امور پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا اور اسے جاوید احمد غامدی کی زیرادارت شائع ہونے والے ماہنامہ اشراق لاہور میں بھی میرے مذکورہ بالا مضمون کے ساتھ شائع کر دیا گیا۔ زیر نظر مضمون میں معز امجد کے اس مضمون کی بعض باتوں پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ سابقہ مضامین مختلف اخبارات میں شائع ہونے کی وجہ سے بیشتر قارئین کے سامنے پوری بحث نہیں ہوگی اس لیے اس کا مختصر خلاصہ ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ بحث کا کوئی پہلو قارئین کے سامنے تشنہ نہ رہے۔
غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ علماء کو سیاست میں فریق بننے کی بجائے اپنا کردار علمی و فکری راہنمائی تک محدود رکھنا چاہیے اور بہتر ہے کہ مولوی کو سیاستدان بنانے کی بجائے سیاستدان کو مولوی بنانے کی کوشش کی جائے۔ راقم الحروف نے اس پر عرض کیا کہ یہ موقع محل کی مناسبت کی بات ہے کہ علماء کرام علمی و فکری راہنمائی اور قیادت کریں یا ضرورت ہو تو حالات کی اصلاح کے لیے خود سیاست میں فریق بننے کا راستہ اختیار کریں۔ دونوں طرف امت کے اہل علم کا اسوہ موجود ہے اور ضرورت کے مطابق کوئی سا راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ خورشید احمد ندیم نے جواب میں اس سے اتفاق کیا کہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں بلکہ حکمت و تدبیر کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان میں علماء کرام کے قومی سیاست میں خود فریق بننے سے دین اور علماء کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوا ہے۔ راقم الحروف نے ان کی اس بات سے اختلاف کیا اور عرض کیا کہ ملک کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کی منظوری صرف اس لیے ہو سکی کہ اسمبلی میں علامہ شبیر احمد عثمانیؒ بطور رکن موجود تھے۔ اور ۱۹۷۳ء کے دستور میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دینے، قران و سنت کے مطابق قانون سازی کی دستوری ضمانت اور دیگر اسلامی دفعات کی شمولیت کی واحد وجہ یہ تھی کہ دستور ساز اسمبلی میں مولانا مفتی محمودؒ ، مولانا شاہ احمد نورانیؒ ، مولانا عبد الحقؒ ، مولانا غلام غوث ہزارویؒ ، مولانا ظفر احمد انصاریؒ ، اور مولانا عبد المصطفیٰ ازہریؒ جیسے سرکردہ علماء نے اس کے لیے مشترکہ طور پر جنگ لڑی۔ اس لیے اگر آج کے شدید بین الاقوامی دباؤ اور عالمی سطح کی مسلسل مخالفت کے باوجود پاکستان دستوری طور پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر قائم ہے اور کفر و استعمار کی آنکھوں میں مسلسل کھٹک رہا ہے تو یہ قومی سیاست میں علماء کرام کے فریق بننے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اس ایک بنیادی اور اصولی فائدہ کے لیے ان نقصانات کو برداشت کیا جا سکتا ہے جو اس سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے سامنے آرہے ہیں۔ اور ہمارے خیال میں یہ فائدہ نقصانات پر بھاری ہے۔
غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ جہاد کا حق صرف اسلامی حکومت کو ہے، اس کی طرف سے اعلان کے بغیر کوئی جنگ جہاد نہیں کہلا سکتی، اس لیے مختلف جہادی گروپوں کی طرف سے کی جانے والی جنگ شرعاً جہاد نہیں ہے۔ راقم الحروف نے اس پر عرض کیا کہ بلاشبہ کسی ملک یا قوم کے خلاف اعلان جنگ مسلمان حکومت ہی کا حق ہے لیکن جب کسی مسلمان آبادی پر کافروں کا جابرانہ تسلط قائم ہو جائے اور مسلمانوں کی حکومت اس تسلط کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار نہ ہو یا اس میں مزاحمت کی سکت نہ رہے تو پھر آزادی کے حصول کے لیے جہاد کا آغاز کسی حکومت کے اعلان یا اجازت پر موقوف نہیں رہے گا۔ اور ایسے موقع پر اگر علماء مسلمان معاشرہ کی قیادت کرتے ہوئے کافر قوت کے تسلط کے خلاف مزاحمت کا اعلان کریں گے تو وہ شرعاً جہاد کہلائے گا۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے برصغیر پاک و ہند کے جہاد آزادی، الجزائر کے جہاد آزادی، اور افغانستان کے جہاد کے ساتھ ساتھ تاتاریوں کی یورش کے خلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے اعلان جہاد کا بھی حوالہ دیا کہ ماضی میں علماء کرام نے ایسے مراحل میں جہاد کا اعلان کیا ہے اور ان کی جدوجہد کو شرعی جہاد ہی کی حیثیت حاصل رہی ہے۔
اس کے جواب میں معز امجد نے طویل بحث کی ہے اور میں اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے اصولی طور پر میرے طرز استدلال سے اختلاف کیا ہے کہ میں نے امت کے اہل علم کے تعامل سے استدلال کر کے غلطی کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ
’’عام انسانوں کی بات بے شک مختلف ہوگی مگر مولانا محترم جیسے اہل علم سے ہماری توقع یہی ہے کہ وہ اہل علم کے عمل سے شریعت اخذ کرنے کی بجائے شریعت کی روشنی میں اس عمل کا جائزہ لیں۔ اگر شریعت اسلامی کے بنیادی ماخذوں یعنی قرآن و سنت میں اس عمل کی بنیاد موجود ہے تو اسے شریعت کے مطابق اور اگر ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو بغیر کسی تردد کے اسے شریعت سے ہٹا ہوا قرار دیں۔‘‘
میرے نزدیک ہمارے درمیان نقطۂ نظر کے اختلاف کا بنیادی نکتہ اور اصل موڑ یہی ہے۔ اگر یہ واضح ہو جائے تو باقی معاملات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت کے اصول دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو قرآن کریم اور سنت نبویؐ سے دلالت صریحہ اور قطعی ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی ان کے مفہوم کے تعین کے لیے کسی استدلال اور استنباط کی ضرورت نہیں اور ثبوت میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور جو فقہاء کی اصطلاح میں صریح الدلالہ اور قطعی الثبوت کہلاتے ہیں ان کے بارے میں تو کسی درجہ میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں ہر بات پر فوقیت حاصل ہے اور کسی بھی شخصیت کے موقف یا طرز عمل کو اس پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی سورۃ التحریم کے مطابق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال و حرام کی واضح اشیاء میں اپنی رائے اور مرضی اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں دیا گیا۔ لیکن شریعت کے جن اصول و احکام کے ثبوت اور استدلال و استنباط کا مدار شخصیات پر ہے اور وہ شخصیات کے استدلال و استنباط ہی کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں ان کے بارے میں بنیادی حیثیت اور ترجیح شخصیات کو حاصل ہے۔ اور شخصیات کے علم و فضل اور درجات میں تفاوت کا اثر ان کے استنباط کردہ اصول و احکام پر لازماً پڑے گا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے جس سے محترم غامدی اور ان کے لائق احترام شاگردان گرامی کو بھی شاید اختلاف نہیں ہوگا۔
سادہ سی بات ہے کہ اگر اصول نے شخصیات کو جنم دیا ہے تو اصول کو ان پر بالادستی ہوگی، اور اگر شخصیات نے اصول قائم کیے ہیں اور اصول کا اپنا وجود ان شخصیات کے استدلال و استنباط کا رہین منت ہے تو ان اصول کو شخصیات پر بالاتر قرار دینے اور ان کے مقابلہ میں شخصیات کی قطعی طور پر نفی کردینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بلکہ خود قرآن کریم کی منشا کو سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اصول بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کے بارے میں شخصیات کی پیروی کی ترغیب دی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے اور ’’صراط مستقیم‘‘ کی وضاحت میں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر شخصیات ہی کو آئیڈیل بنانے کا راستہ دکھایا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں صحابہ کرامؓ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر باقی لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسا ایمان تم لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں گے۔ اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ ایمان کے معاملہ میں صحابہ کرامؓ کی شخصیات کو معیار اور آئیڈیل قرار دیا گیاہے۔ اس لیے اہل علم اور شخصیات سے شریعت اخذ کرنے کی بات نہ تو قرآن کریم کی منشا کے خلاف ہے اور نہ ہی عقل و منطق اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔
اس سلسلہ میں دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام و اصول اہل علم اور شخصیات کے استدلال و استنباط کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، ان احکام و اصول کی ترجیحات بھی اہل علم اور شخصیات کے درمیان موجود ترجیحات کے ساتھ ساتھ اپنی ترتیب قائم کریں گی۔ اور اسی ترتیب و ترجیح کے فہم و ادراک اور تشکیل و اطلاق کا نام فقہی تدبر ہے جس نے فقہائے امت کو اہل علم کے دیگر تمام طبقات پر فوقیت اور امتیاز عطا کیا ہے۔ شریعت کے ہر حکم کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے اور اس سے صحیح طور پر استفادہ کے لیے ان ترجیحات کا لحاظ ناگزیر ہے ورنہ شریعت پر عمل کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔
اسی ضمن میں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ ہر دور میں اس دور کی ضروریات کے مطابق اصول وضع کیے گئے ہیں اور انہی ضروریات کے تحت ان کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ اس لیے قطعی اور صریح اصولوں کو بالاتر رکھتے ہوئے ظنی اور استدلالی اصولوں کو ان کی ضروریات کے دائرہ تک محدود رکھنا اور انہیں وضع کرنے والے اہل علم اور شخصیات کی ترجیحات کے معیار پر ان کی ترتیب قائم کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بعض اصولی حضرات ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ جب وہ خود اپنے وضع کردہ اصولوں کا اطلاق پوری امت پر کرنے لگتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ امت کا بیشتر حصہ انہیں اپنے اصولوں پر عمل کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور ان کی اصول پرستی انہیں اس بات پر ابھارنے لگتی ہے کہ وہ اپنے قائم کردہ اصولوں کی لاٹھی اٹھا کر اس کے ساتھ پوری امت کے اہل علم کو ہانکنے لگ جائیں۔
اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک عملی مثال دینا چاہوں گا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک دوست میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہؒ نے حضرت امام بخاریؒ کی طرح احادیث نبویؐ کے جمع کرنے اور ان کی صحت کے اصول قائم کرنے پر کوئی کام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں اور انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرا یہ جواب ان کے لیے حیرت کا باعث بنا اور انہوں نے قدرے غصے سے فرمایا کہ کیا امام ابوحنیفہؒ کو احادیث کی ضرورت نہیں تھی؟ میں نے جواب دیا کہ احادیث کی ضرورت تھی لیکن ان پر امام بخاریؒ کی طرز کے کام کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کی وضاحت کی کہ امام ابوحنیفہؒ ۸۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ یہ صحابہ کرامؓ کا آخری دور تھا اور کوفہ صحابہ کرامؓ کا مرکز تھا۔ اس لیے امام صاحبؒ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے صغار صحابہؓ اور کبار تابعینؒ کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ ان کی وفات ۱۵۶ھ میں ہوئی اور ان کے دور میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث و سنن کی روایت میں اتنے واسطے نہیں ہوتے تھے کہ ان کی چھان بین کی زیادہ ضرورت پڑتی۔ اس لیے انہوں نے ایک دو قابل اعتماد واسطوں سے جو روایات ملیں انہی کی بنیاد پر اپنی فقہ کی عمارت کھڑی کر دی۔ جبکہ امام بخاریؒ کی ولادت ۱۹۴ھ اور وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی۔ اس وقت احادیث کی روایت میں چار پانچ واسطے آچکے تھے اور ان کی صحت و ضعف کے لیے سخت اصول قائم کرنے کی ضرورت پیش آگئی تھی۔ اس لیے امام بخاریؒ نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اصول قائم کیے اور ان کی بنیاد پر صحیح احادیث کا ایک منتخب ذخیرہ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے امام بخاریؒ کے وضع کردہ اصول کی اہمیت اپنی جگہ پوری طرح مسلم ہے لیکن ان اصولوں کا پون صدی پہلے پر موثربہ ماضی اطلاق کر کے امام ابوحنیفہؒ کو ان کا پابند بنانا نہ شریعت کا تقاضا ہے اور نہ عقل و دانش اس کی متحمل ہے۔
اس پس منظر میں محترم جاوید غامدی صاحب اور ان کے رفقاء سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا حمید الدین فراہیؒ کے استدلال و استنباط اور ان کے قائم کردہ اصولوں کی اہمیت سے انکار نہیں اور اہل علم کے درمیان مسلمہ حدود کے دائرہ میں ان سے استفادہ کی ضرورت سے بھی ہم صرف نظر نہیں کر رہے۔ مگر ان اصولوں کا اطلاق ماضی کے ہر دور کے اہل علم پر کر کے پوری امت کے اہل علم کے تعامل اور مسلسل طرز عمل کی نفی کر دینا بھی دانش مندی کا تقاضا نہیں۔
اس سلسلہ میں تیسری گزارش ہے کہ جس کی طرف ہم اپنے سابقہ مضامین میں اصولی فقہاء اور عملی فقہاء کی اصطلاح کے ساتھ اشارہ کر چکے ہیں کہ اصول وضع کرنا ایک مختلف عمل ہے اور سوسائٹی کے عملی مسائل پر ان کا اطلاق کر کے قواعد و احکام مستنبط کرنا اس سے مختلف عمل کا نام ہے۔ آج کی اصطلاح میں اسے دستور سازی اور قانون سازی کے اصولی کام اور سوسائٹی میں عملی طور پر اس کے نفاذ کے عدالتی عمل کے درمیان فرق سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے سے بسا اوقات مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور عملی مشکلات کا لحاظ نہ کر کے صرف اصول کی بنیاد پر فیصلے کرتے چلے جانے سے ایسی الجھنیں جنم لیتی ہیں جن کا حل بظاہر مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ اس اصولیت محضہ کا اظہار سب سے پہلے خوارج نے کیا تھا جنہوں نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ اصول وضع کیے اور ان اصولوں پر اس قدر سختی دکھائی کہ بعض حضرات نے صحابہ کرامؓ تک کی تکفیر کر ڈالی۔ مثلاً انہوں نے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان بپا ہونے والی صفین کی جنگ مین حضرت علیؓ کی طرف سے تحکیم پر راضی ہونے سے اختلاف کرتے ہوئے ان کے لشکر سے علیحدگی اختیار کی۔ ان کی بغاوت اور علیحدگی کے بعد حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ان کے پاس حضرت علیؓ کے نمائندہ کے طور پر گفتگو کے لیے گئے تو امام نسائی کی ’’سنن کبریٰ‘‘ کی روایت کے مطابق ان خوارج نے حضرت علیؓ پر جو اعتراضات کیے ان میں ایک یہ تھا کہ اگر حضرت معاویہؓ اور ان کے رفقاء مسلمان ہیں تو ان کے خلاف جنگ لڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو جنگ میں ان کے قیدیوں کو غلام کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنگ تو ام المومنین حضرت عائشہؓ کے ساتھ بھی ہوئی تھی، کیا تم (نعوذ باللہ) انہیں لونڈی بنانا پسند کرو گے؟ اس کا جواب خوارج کے پاس کوئی نہیں تھا چنانچہ چھ ہزار خوارج میں سے دو ہزار افراد اس بات پر ان کا ساتھ چھوڑ کر حضرت علیؓ کے کیمپ میں واپس آگئے تھے۔
اس لیے اصول، اہل علم اور شخصیات میں توازن کے حوالہ سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ
- قرآن و سنت کے بیان کردہ قطعی اور صریح اصولوں کو ہر چیز پر فوقیت اور بالاتری حاصل ہے۔
- جو اصول اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں خود مستنبط کیے ہیں ان میں اصل مدار شخصیات پر ہے اور شخصیات کی باہمی ترجیحات ان کے وضع کردہ اصولوں میں بھی کارفرما ہوں گی۔
- ظنی اور استنباطی اصولوں اور سوسائٹی میں ان کے اطلاق و تطبیق کی عملی مشکلات دونوں کو سامنے رکھ کر احکام و ضوابط طے کیے جائیں گے۔
- بعد میں پیش آنے والی ضروریات کے لیے وضع کیے جانے والے اصولوں کا موثر بہ ماضی اطلاق ضروری نہیں ہوگا اور نہ ہی ماضی کے معاملات کا ان کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔
- صحابہ کرامؓ کا دور چونکہ ان سب استنباطات، استدلالات اور اجتہادات سے مقدم ہے اور وہ چشمہ نبوت سے براہ راست فیض یاب ہوئے ہیں، اس لیے قرآن و سنت کے مفہوم و مصداق کے تعین اور بعد میں آنے والے اصولوں کے تعارض و تضاد کے حل کے لیے ان کا تعامل حتمی حجت ہے۔
اس اصولی بحث کے بعد میں جہاد کے مسئلہ کی طرف آتا ہوں جس میں ہمارے درمیان اختلاف کا نکتہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک یا آبادی پر کفار کا تسلط قائم ہو جائے تو کیا مسلمان آبادی یا ان کے علماء کسی باضابطہ حکومت کے قیام کے بغیر اس تسلط کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی صورت میں علماء کرام کو جہاد کے اعلان کا حق حاصل ہے اور ان کے اعلان کی بنیاد پر لڑی جانے والی جنگ شرعاً جہاد کہلائے گی۔ جیسے جنوبی ایشیا میں برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف، الجزائر میں فرانسیسی استعمار کے تسلط کے خلاف، اور افغانستان میں روسی استعمار کے تسلط کے خلاف آزادی کی جنگ علماء کے فتویٰ پر جہاد کے عنوان سے لڑی گئی ہے۔ مگر معز امجد ان میں سے کسی جنگ کو جہاد قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہوں نے جواب میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے ان کے بقول مسلمانوں کی آبادی پر کافروں کے تسلط کی صورت میں دو ہی راستے بتائے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ اگر ہجرت کا راستہ اور مقام موجود ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہجرت قابل عمل نہ ہو تو صبر و شکر کر کے بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ انہوں نے اس سلسلہ میں سورۃ النساء، سورۃ الانفال اور سورۃ الاعراف کی بعض آیات کریمہ کا حوالہ بھی دیا ہے۔
مگر افسوس ہے کہ وہ مسئلہ کی نوعیت ہی کو سرے سے نہیں سمجھ سکے۔ کیونکہ ان آیات کریمہ میں ان مسلمانوں کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں جو کافروں کی سوسائٹی میں مسلمان ہوگئے ہیں اور ان کے زیر اثر رہ رہے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں تو نکل جائیں ورنہ صبر و حوصلہ کے کے ساتھ حالات کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ جبکہ ہم جس صورت پر بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی پر باہر سے آکر کافروں نے تسلط جما لیا ہے اور مسلمان اکثریت پر کافر اقلیت کا جبر و اقتدار قائم ہوگیا ہے اس صورت میں محترم غامدی اور ان کے تلامذہ ہی مسلم اکثریت کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا علاقہ کافر غالبین کے حوالہ کر کے وہاں سے چلے جائیں یا ان کے جبر و ظلم کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے جائیں۔ ورنہ ہمیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے برعکس رہنمائی ملتی ہے۔
یمن کا علاقہ جناب نبی اکرمؐ کے دور میں مسلم مملکت میں شامل ہوگیا تھا اور شہر بن باذانؓ کو رسول اللہؐ نے اپنی طرف سے وہاں کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ یمن کے مختلف علاقوں میں حضرت علیؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، اور دوسرے عمال کا تقرر کیا تھا۔ مگر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر کے صنعا پر چڑھائی کی اور شہر بن باذانؓ کو قتل کر کے یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ مقتول گورنر کی بیوی کو زبردست اپنے حرم میں داخل کیا، یمن کے مختلف علاقوں سے جناب نبی اکرمؐ کے مقرر کردہ عاملوں کو نکال دیا، اور اس طرح یمن کا صوبہ اسلامی حکومت سے نکل کر کافروں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس پر تین حضرات حضرت فیروز ویلمیؓ، حضرت قیس بن مکشوحؓ، اور حضرت دادویہؓ نے باہمی مشورہ کر کے گوریلا طرز جنگ پر شبخون مارنے کا پروگرام بنایا۔ مقتول مسلمان گورنر شہر بن باذانؓ کی بیوی سے جو اسود عنسی نے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر رکھی تھی، ان تینوں حضرات نے رابطہ کر کے ساز باز کی جس کے تحت اس نے رات کو اسود عنسی کو بہت زیادہ شراب پلا دی، ان حضرات نے محل کی دیوار میں نقب لگا کر اندر داخل ہونے کا راستہ نکالا اور رات کی تاریکی میں اسود عنسی اور اس کے پہرہ داروں کو قتل کر کے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ یہ گوریلا کاروائی تھی اور مسلح کاروائی تھی۔ اس میں معز امجد صاحب کو یقیناًکچھ اخلاقی خرابیاں نظر آرہی ہوں گی اور بلا ضرورت قتل و غارت بھی دکھائی دیتی ہوگی۔ لیکن عملاً یہ سب کچھ ہوا جس کے نتیجہ میں یمن پر مسلمانوں کا اقتدار دوبارہ بحال ہوا ۔ اور جناب نبی اکرمؐ کو جب ان کے وصال سے صرف دو روز قبل وحی کے ذریعہ اس کارروائی کی خبر ملی تو آپؐ نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کرامؓ کو یہ خوشخبری سنائی فاز فیروز کہ فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہوگیا ہے۔ اس کے بعد حضرت فیروز ویلمیؓ جب اس کامیابی کی خبر لے کر یمن سے مدینہ منورہ پہنچے تو جناب نبی اکرمؐ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رپورٹ خلیفۂ اول حضرت صدیق اکبرؓ کو پیش کی اور انہوں نے اس پر اطمینان اور مسرت کا اظہار فرمایا۔
اس لیے محترم معز امجد صاحب سے عرض ہے کہ جن آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان کا مصداق یہ نہیں ہے بلکہ اس کی عملی شکل وہی یمن والی ہے کہ جب کسی مسلمان ملک پر کافروں کا تسلط قائم ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو صورت بھی اس وقت کے حالات کی روشنی میں اختیار کر سکیں اس سے گریز نہ کریں۔ اور وہ کافر و ظالم قوت کے جابرانہ تسلط کے خلاف مزاحمت کی جو صورت بھی اختیار کریں گے وہ حضرت فیروز ویلمیؓ کی اس گوریلا کاروائی اور شبخون کی طرح جہاد ہی کہلائے گی۔
زکوٰۃ کے بارے میں جناب جاوید غامدی نے فرمایا تھا کہ اسلامی مملکت میں اجتماعی معیشت کے نظام کو چلانے کے لیے زکوٰۃ ہی کا نظام کافی ہے اس کے علاوہ اسلام نے حکومت کو اور کوئی ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ درست ہے کہ اگر زکوٰۃ اور دیگر شرعی واجبات کا نظام صحیح طور پر قائم ہو جائے تو معاشرہ کی اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی درست ہے کہ ٹیکسوں کا مروجہ نظام سراسر ظالمانہ ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وقت قومی ضروریات زکوٰۃ اور بیت المال کی دیگر شرعی مدات سے پوری نہ ہوں تو کیا حکومت وقتی ضرورت کے لیے کوئی اور ٹیکس جائز حد تک لگانے کی مجاز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ممانعت کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل غامدی صاحب کے پاس موجود ہو تو وہ رہنمائی فرمائیں۔
اس کے جواب میں معز امجد صاحب نے قرآن کریم کی بعض آیات اور جناب نبی اکرمؐ کے بعض ارشادات سے استدلال کیا ہے مگر یہ استدلال ان کے موقف کی تائید نہیں کرتا۔ مثلاً انہوں نے سورۃ التوبہ کی آیت ۵ کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کرلیں، نماز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں تو فخلوا سبیلہم ان کی راہ چھوڑ دو۔ یہاں ان کی راہ چھوڑ دو سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ان سے اور کوئی مالی تقاضہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ مگر اس کی وضاحت میں مسلم شریف کی جو روایت انہوں نے پیش کی ہے اس میں جناب نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت دے دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جب وہ ایسا کریں تو ان کی جانیں اور ان کے اموال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہاں اموال کے محفوظ ہوجانے کا مفہوم معز امجد صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ ان سے مزید کوئی مالی تقاضہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر ان کے بیان کردہ مفہوم کو صحیح سمجھ لیا جائے تو بھی اس روایت میں الا بحقھا کی استثناء موجود ہے جو خود انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ جس سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ اسلام کے حقوق کے حوالہ سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کا تقاضہ مسلمانوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ابن ماجہ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ جناب نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ترمذی کے حوالہ سے جناب نبی اکرمؐ کا یہ ارشاد بھی نقل کر دیا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے۔
اس لیے میرے خیال میں یہ آیات اور روایات غامدی صاحب کے موقف کی بجائے ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں کہ ضرورت پڑنے پر زکوٰۃ کے علاوہ مزید ٹیکس بھی اسلامی حکومت کی طرف سے عائد کیا جا سکتا ہے۔
اس سلسلہ میں مولانا مناظر احسن گیلانیؒ کی ’’اسلامی معاشیات‘‘ اور مولانا حفظ الرحمان کی ’’اسلام کا اقتصادی نظام‘‘ کا حوالہ دوں گا جس میں انہوں نے ’’ضرائب‘‘ اور ’’نوائب‘‘ کے عنوان سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور حضرت علیؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، ۔۔۔۔۔۔ امام ابن حزم اندلسیؒ اور فقہائے احناف میں سے صاحب ہدایہؒ اور علامہ ابن حاثمؒ صاحب فتح القدیر کے ارشادات و تصریحات کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ اجتماعی ضروریات مثلاً نہر کھودنے، دفاعی تیاریوں، فوج کی تنخواہ، اور قیدیوں کی رہائی وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ مزید ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں۔ البتہ ہنر مندوں اور کاروباری لوگوں پر ان کے ہنر یا کاروبار کے حوالہ سے جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ ظالمانہ ہیں اور شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی علامہ ابن ہمام حنفیؒ لکھتے ہیں کہ
’’ہمارے زمانے میں یہ عموماً جو محصول وصول کیے جاتے ہیں چونکہ یہ ظلماً وصول کیے جاتے ہیں اس لیے ظلم کے ازالہ کا جتنا کسی کو موقع مل سکے اس کے لیے بہتر ہے۔‘‘
چنانچہ ٹیکسوں کے باب میں یہ بحث تو موجود ہے کہ کون سا ٹیکس جائز ہے اور کونسا ناجائز۔ اور یہ مسئلہ بھی بحث طلب ہے کہ وصولی کا کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ لیکن اصولی طور پر قومی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ اسلامی حکومت جائز حد تک دیگر ٹیکس بھی لگا سکتی ہے اور اس کی کوئی واضح شرعی ممانعت موجود نہیں ہے۔
فتویٰ کے بارے میں غامدی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علماء کرام کے آزادانہ فتوے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں اس لیے فتویٰ دینے کے حق کو ریاستی قوانین کے تابع ہونا چاہیے۔ اسی پس منظر میں انہوں نے بنگلہ دیش ہائی کورٹ کے اس حالیہ فیصلے کو صدی کا بہترین فیصلہ قرار دیا ہے جس میں علماء کرام کے آزادانہ طور پر فتویٰ دینے کے حق کو سلب کر لینے کی بات کی گئی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ غامدی صاحب کا یہ ارشاد فتویٰ کے مفہوم اور اس حوالہ سے امت کے اجتماعی تعامل کے منافی ہے جس پر ہر دور میں جمہور علماء کا عمل رہا ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض غیر ذمہ دار حضرات کے فتوے خرابیوں کا باعث ضرور بن رہے ہین جس طرح عدالتوں میں ہر سطح پر رشوت اور بدعنوانی عام ہو جانے پر سب ججوں سے فیصلہ کرنے کا حق واپس لینے کی بات قرین انصاف نہیں ہے اسی طرح فتوؤں میں غیر ذمہ دارانہ رجحان بڑھنے پر تمام علماء کرام سے فتویٰ کا حق سلب کر لینا بھی قرین قیاس نہیں ہے۔
اس کے جواب میں معز امجد صاحب نے طویل بحث کی ہے جس کا خلاصہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ علماء کرام کے جو فتاویٰ پارلیمان اور عدالت کے معاملات میں رخنہ ڈالتے ہیں وہ اجتماعی نظم میں خرابی پیدا کرتے ہیں ان پر ضرور پابندی عائد ہونی چاہیے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات فتویٰ کے مفہوم اور اس کے دائرہ کار دونوں کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ فتویٰ کہتے ہی کسی مسئلہ پر آزادانہ شرعی رائے کو ہیں۔ اگر کسی مسئلہ پر کوئی حاکم انتظامی فیصلہ دے گا تو وہ شرعی اصطلاح میں ’’امر‘‘ کہلائے گا۔ اور کوئی عدالت فیصلہ صادر کرے گی تو اسے ’’قضا‘‘ کہا جائے گا۔ جبکہ اگر کسی سوال پر کوئی عالم دین اپنے علم و تجربہ کی روشنی میں شرعی رائے دے گا تو وہ ’’فتویٰ‘‘ قرار پائے گا، اس میں سے اگر آزادانہ رائے کا عنصر نکال دیا جائے تو وہ سرے سے فتویٰ ہی نہیں رہتا۔ وہ یا تو حکم بن جائے گا یا قضا کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے فتویٰ کے طور پر باقی رکھنے کا ناگزیر تقاضہ ہے کہ اس کی آزادی بھی قائم رہے۔
اسی طرح فتویٰ کا دائرہ کار صرف شرعی رائے کا اظہار ہے، کسی انتظامی حکم کو منسوخ کرنے یا کسی عدالت کے فیصلے کو نامعلوم قرار دینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے وہ کسی صورت میں بھی انتظامیہ اور عدلیہ کے لیے چیلنج نہیں بن سکتا اور نہ ہی اس سے اجتماعی نظام میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی نظم میں خرابی وہاں پیدا ہوگی جہاں انتظامیہ اور عدلیہ لوگوں کی شرعی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہیں گی اور لوگ ان سے مایوس ہو کر علماء کرام کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوں گے جیسا کہ آج کل اکثر مسلم ممالک میں ہو رہا ہے۔ مگر اس کی ذمہ داری فتویٰ کے نظام پر نہیں بلکہ عدالتی اور انتظامی سسٹم پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کسی مسلم معاشرہ کا اجتماعی نظم اگر اپنے افراد کو شریعت کے مطابق عدالتی اور انتظامی احکامات فراہم نہیں کر رہا اور مسلمان اپنے دین پر عملدرآمد کے خواہش مند ہیں تو عام مسلمانوں کو شرعی مسئلہ پوچھنے اور علماء کو اس کا جواب دینے کے حق سے محروم کرنا اس سسٹم کو مستحکم کرنے کے مترادف ہوگا جو ایک مسلمان معاشرہ کو غیر اسلامی نظام کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ جس کی کم از کم جاوید احمد غامدی صاحب جیسے صاحب علم سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً بنگلہ دیش کا معاملہ لے لیجیے جہاں دستوری طور پر سیکولر نظام نافذ ہے اور عدالتی سسٹم بھی اسی نظام کے تابع ہے۔ اس لیے اس سسٹم میں علماء کو پابند کرنا کہ وہ کسی معاملہ میں شرعی رائے کا اظہار بھی ریاستی قوانین کے دائرہ سے ہٹ کر نہ کریں، ایک سیکولر نظام کو تقویت دینے اور دینی اقدار کو مزید کمزور کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اکثر مسلم ممالک میں اس وقت عملاً سیکولر نظام نافذ ہے۔ خود ہمارے ہاں پاکستان میں بھی دستوری طور پر اسلامی ریاست ہونے کے باوجود عملی نظام کی بنیادی سیکولر ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری عدالتوں میں بھی برطانوی دور کا نو آبادیاتی نظام بدستور چلا آرہا ہے۔ بلکہ ترکی کی مثال اس سے زیادہ واضح ہے کہ وہاں شرعی احکام پر عمل کرنے کی ہی سرے سے ممانعت ہے۔ ان ممالک میں اگر کوئی مسلمان شہری قرآن و سنت کے احکام اور شرعی ضوابط کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ علماء کرام سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اکثر مسلم ممالک میں شرعی احکام و قوانین کی وضاحت اور کسی حد تک ان پر عملدرآمد کا یہی ایک آخری ادارہ باقی رہ گیا ہے۔ کیا محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے شاگردان گرامی مولوی کی مخالفت اور اسے نیچا دکھانے کے شوق میں سیکولر سسٹم کے مقابل اس آخری مورچے کو بھی گرا دینا چاہتے ہیں؟
مجھے ان باتوں سے اتفاق نہیں
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
پشاور کے سید وقار حسین صاحب نے ایک خط میں منیر احمد چغتائی صاحب آف کراچی کے اس مراسلہ کی طرف توجہ دلائی ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب کے بعض افکار کے بارے میں میرے مضامین کے حوالہ سے گزشتہ دنوں روزنامہ اوصاف میں شائع ہوا ہے۔ یہ مراسلہ میری نظر سے گزر چکا ہے اور میں نے اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا کہ اس کی بعض باتوں پر کسی کالم میں تبصرہ کر دوں گا۔ مگر وقار حسین کے توجہ دلانے پر اپنی ترتیب میں رد و بدل کر کے اس مراسلہ کے بارے میں ابھی کچھ عرض کر رہا ہوں۔
چغتائی صاحب کے مراسلہ کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ غامدی صاحب میدان سے بھاگ گئے ہیں، اور اس کے بعد دوسری قابل توجہ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ غامدی صاحب جہاد کے بارے میں قادیانیوں کے موقف کے موید ہیں۔ مجھے چغتائی صاحب کی ان دونوں باتوں سے اتفاق نہیں ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس گفتگو کا آغاز غامدی صاحب کو میدان سے بھگانے کے لیے نہیں کیا تھا اور نہ انہیں بھاگنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ خالص مناظرانہ اسلوب کی باتیں ہیں جو نہ میرے مزاج کا حصہ ہیں اور نہ ہی غامدی صاحب اس اسلوب کے دانشور ہیں۔ میں نے ان کے بعض افکار پر برادرانہ انداز میں افہام و تفہیم کے جذبہ کے تحت اظہار خیال کیا تھا جس کے جواب میں ان کے دو شاگردوں خورشید احمد ندیم اور معز امجد نے طبع آزمائی کی مگر ان کے جوابات سے مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوا جس کا اظہار میں نے بے تکلفی کے ساتھ بعد کے مضامین میں کر دیا۔ اب دونوں طرف کے مضامین اہل علم کے سامنے ہیں اور وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کے موقف اور دلائل میں کتنا وزن ہے۔ اس میں ہار جیت یا میدان میں ٹھہرنے اور بھاگنے کا کوئی سوال نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کا نتیجہ اخذ کرنا اس قسم کے علمی مباحث سے مناسبت رکھتا ہے۔
جہاں تک غامدی صاحب کو جہاد کے بارے میں قادیانیوں کے موقف کا موید ظاہر کرنا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس لیے کہ ان کا موقف قطعاً وہ نہیں ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے جہاد کے سرے سے منسوخ ہونے کا اعلان کیا تھا بلکہ اس کی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ ہی جہاد کی منسوخی کے پرچار کے لیے رچایا گیا تھا۔ جبکہ غامدی صاحب جہاد کی فرضیت اور اہمیت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں، البتہ جہاد کے اعلان کی مجاز اتھارٹی کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں اور اس بارے میں ان کی رائے امت کے جمہور اہل علم سے مختلف ہے جس پر ہم تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کر چکے ہیں۔
اپنے سابقہ مضامین میں عرض کر چکا ہوں کہ میں غامدی صاحب کو حضرت مولانا حمید الدین فراہیؒ کے علمی مکتب فکر کا نمائندہ سمجھتا ہوں۔ اور مولانا فراہیؒ کے بارے میں میری رائے وہی ہے جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ اور حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ کی ہے، البتہ امت کے جمہور اہل علم کے علی الرغم ان کے تفردات کو میں قبول نہیں کرتا۔ اور غامدی صاحب سے میں نے یہی عرض کیا ہے کہ علمی تفردات کو اس انداز سے پیش کرنا کہ وہ امت کے اجتماعی علمی دھارے سے الگ کسی نئے مکتب فکر کا عنوان نظر آنے لگیں، امت میں فکری انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر اس پر اصرار کیا جائے تو اسے عالمی فکری استعمار کی ان کوششوں سے الگ کر کے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے جو ملت اسلامیہ کو ذہنی انتشار اور فکری انارکی سے دوچار کرنے کے لیے ایک عرصہ سے جاری ہیں۔
اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ قبل ایک صاحب علم دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ علمی تفردات میں مولانا ابوالکلام آزادؒ اور مولانا عبید اللہ سندھیؒ بھی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ سے پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے تفردات علماء کے حلقہ میں اس شدت کے ساتھ موضوع بحث نہیں بنے جس شدت کے ساتھ مولانا مودودیؒ کے افکار کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا سندھیؒ اور مولانا ابوالکلام آزادؒ کے علمی تفردات پر ان کے شاگردوں اور معتقدین نے دفاع اور ہر حال میں انہیں صحیح ثابت کرنے کی وہ روش اختیار نہیں کی جو خود مولانا مودودیؒ اور ان کے رفقاء نے ان کی تحریروں پر علماء کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات پر اپنا لی تھی۔ چنانچہ اس روش کے نتیجہ میں وہ جمہور علماء کے مد مقابل ایک فریق کی حیثیت اختیار کرتے چلے گئے اور بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہوگیا۔
اس حوالہ سے قریبی زمانہ میں سب سے بہتر طرز عمل اور اسوہ میرے نزدیک حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ہے جنہیں جب بھی ان کی کسی رائے کے غلط ہونے کے بارے میں دلیل کے ساتھ بتایا گیا تو انہوں نے اس سے رجوع میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں کی۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق آخر عمر میں انہوں نے علماء کے ایک گروپ کے ذمہ لگا دیا تھا کہ وہ ان کی تصانیف کا مطالعہ کر کے ایسی باتوں کی نشاندہی کریں جو ان کے نزدیک سلف صالحینؒ اور جمہور اہل علم کے موقف سے مطابقت نہ رکھتی ہوں تاکہ وہ ان پر نظر ثانی کر سکیں۔
یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ’’اصول پرستی‘‘ کی کچھ حدود ہیں اور اصول قائم کرتے وقت ان کے عملی اطلاق کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے ورنہ مسائل سلجھنے کی بجائے مزید الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اصول کی درجہ بندی بھی ہے۔ وہ اصول جو قرآن و سنت میں قطعیت اور صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں وہ تو قطعی ہیں اور ان کی پابندی سے کوئی بھی شخصیت مستثنیٰ نہیں ہے۔ مگر جو اصول اہل علم نے استنباط اور استدلال کے ذریعہ خود وضع کیے ہیں ان کو قطعیت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی شخصیت یا حلقہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے وضع کردہ اصولوں کو پوری امت کے لیے حتمی قرار دے کر امت کے تمام طبقات کو ان پر پرکھنا شروع کر دے۔ البتہ ان میں سے جس اصول کو امت میں اجماع کا درجہ حاصل ہو جائے یا کم از کم جمہور علماء اس سے اتفاق کا اظہار کر دیں تو اس کی بات مستثنیٰ ہے۔
مولانا زاہد الراشدی کے فرمودات کا جائزہ
معز امجد
غیر مسلکی تسلط کے خلاف جہاد
ماہنامہ ’’اشراق‘‘ مارچ ۲۰۰۱ء میں استاذِ گرامی کی بعض آرا سے متعلق مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ العالی کے فرمودات اور ان کے حوالے سے ہماری معروضات شائع ہوئی ہیں۔ مولانا محترم نے استاذِ گرامی کی جن آرا پر اظہارِ خیال فرمایا ہے ان میں سے ایک جہاد کے متعلق ہمارے استاذ کی رائے ہے۔ یہ بات مولانا محترم کے فرمودات ہی سے واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ’’کسی قوم یا ملک کے خلاف جہاد تو بہرحال مسلمان حکومت ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔‘‘ اپنی معروضات میں ہم نے مولانا محترم کے ساتھ اپنے اختلاف کو واضح کرتے ہوئے لکھا تھا:
’’اب ہمارے اور مولانا کے درمیان اختلاف صرف اسی مسئلے میں ہے کہ اگر کبھی مسلمانوں پر کوئی بیرونی قوت اس طرح سے تسلط حاصل کر لے کہ مسلمانوں کا نظمِ اجتماعی اس کے آگے بالکل بے بس ہو جائے تو اس صورت میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ واضح رہے کہ ایسے حالات میں مولانا ہی کی بات سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ بیرونی طاقت کے خلاف اگر مسلمانوں کا نظمِ اجتماعی اپنی سلطنت کے دفاع کا انتظام کرنے کو آمادہ ہو تو اس صورت میں بھی مسلمانوں کے نظمِ اجتماعی ہی کی طرف سے کی جانے والی جدوجہد ہی اس بات کی مستحق ہو گی کہ اسے جہاد قرار دیا جائے۔ مزید برآں ایسے حالات میں نظمِ اجتماعی سے ہٹ کر، جتھہ بندی کی صورت میں کی جانے والی ہر جدوجہد، غلط قرار پائے گی۔ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ مولانا کو ہماری اس بات سے اتفاق ہو گا، تاہم پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ مولانا ہمارے اس خیال کی تصدیق یا تردید ضرور فرما دیں، تاکہ اس معاملے میں قارئین کے ذہن میں بھی کوئی شک باقی نہ رہے۔ چنانچہ ہمارے فہم کی حد تک، اب ہمارے اور مولانا کے درمیان اختلاف صرف اس صورت سے متعلق ہے جب مسلمانوں کا نظمِ اجتماعی، کسی بھی وجہ سے، بیرونی طاقت کے تسلط کے خلاف جدوجہد کرنے سے قاصر ہو۔ مولانا کے نزدیک اس صورت میں مسلمانوں کو ہر حال میں اپنی سلطنت کے دفاع کی جدوجہد کرنی چاہیے، خواہ یہ جدوجہد غیر منظم جتھہ بندی ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ مزید یہ کہ اس ضمن میں جو منظم یا غیر منظم جدوجہد بھی مسلمانوں کی طرف سے کی جائے گی، وہ مولانا محترم کے نزدیک ’جہاد ‘ہی قرار پائے گی۔‘‘
ہم نے مولانا محترم کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا:
’’دین و شریعت کی رو سے جہاد و قتال کی غیر منظم جدوجہد، بالعموم، جن ہمہ گیر اخلاقی و اجتماعی خرابیوں کو جنم دیتی ہے، شریعتِ اسلامی انہیں کسی بڑی سے بڑی منفعت کے عوض بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآنِ مجید اور انبیاے کرام کی معلوم تاریخ سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جبر و استبداد کی قوتوں کے خلاف، خواہ یہ قوتیں اندرونی ہوں یا بیرونی، اسی صورت میں تلوار اٹھانے کا حکم اور اس کی اجازت دی، جب مسلمان اپنی ایک خودمختار ریاست قائم کر چکے تھے۔ اس سے پہلے کسی صورت میں بھی انبیاے کرام کو کسی جابرانہ تسلط کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔‘‘
اس کے بعد ہم نے جابرانہ تسلط کی مختلف صورتیں اور ان کے بارے میں دین و شریعت کا حکم اور اللہ کے اولوالعزم پیغمبروں کا اسوہ بیان کیا تھا۔ ہماری اس بحث کا خلاصہ اس طرح سے ہے:
۱۔ ایسا جابرانہ تسلط، جہاں محکوم قوم کو اپنے اختیار کردہ مذہب و عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو۔
اس صورت میں جابرانہ تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا ہر محکوم قوم کا حق تو بے شک ہے لیکن یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوہ سے یہی رہنمائی ملتی ہے۔
۲۔ ایسا جابرانہ تسلط، جہاں محکوم کو اپنے اختیار کردہ مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل نہ ہو۔
اس صورت میں اگر محکوم قوم کے لیے جابرانہ تسلط کے علاقے سے ہجرت کر جانے کا موقع موجود ہو تو اس کے لیے دین و شریعت کا حکم یہی ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی خاطر وہ اپنے ملک و قوم کو خیرباد کہہ دیں۔ حضرت موسٰی اور نبی اکرم کے اسوہ سے یہ رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے برعکس، محکوم قوم کے لیے اگر ہجرت کی راہ مسدود ہو تو ان حالات میں درج ذیل دو امکانات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں:
اولاً، محکوم قوم اپنی مدد کے لیے کسی منظم اسلامی ریاست سے مدد طلب کرے۔ قرآن مجید کے مطابق، اگر اس اسلامی ریاست کے لیے ظلم و جبر کا نشانہ بنے بغیر ان مسلمانوں کی مدد کرنی ممکن ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے، الّا یہ کہ جس قوم کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے اور مسلمانوں کی اس ریاست کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ موجود ہو۔ (انفال ۸ : ۷۲ ، نسا ۴ : ۷۵)
ثانیاً، محکوم قوم کے لیے کسی منظم ریاست سے استمداد یا کسی منظم ریاست کے لیے اس محکوم قوم کی مدد کرنے کی راہ مسدود ہو۔ اس صورت میں محکوم قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا اسوہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ آنے تک حالات پر صبر کریں۔ (اعراف ۷ : ۸۷)
روزنامہ ’’اوصاف‘‘ کی ۱۵ اور ۱۶ مارچ کی اشاعت میں مولانا محترم نے ہمارے استدلال کا محاکمہ کیا ہے۔ ہم مولانا محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس طالب علم کی بات کو قابل اعتنا سمجھا اور اس میں غلطی واضح کرنے کے لیے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر مولانا کی توجہ اسی طرح سے ہمیں نصیب رہی تو ان شاء اللہ صحیح بات پوری طرح سے نکھر کر سامنے آ جائے گی۔
اپنے پہلے مضمون میں مولانا محترم نے اپنے استدلال کی بنا فلسطین، برصغیر پاک و ہند، افغانستان اور الجزائر کی جدوجہدِ آزادی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ان کوششوں پر رکھی تھی جو انہوں نے تاتاریوں کے خلاف اہلِ دمشق میں جہاد کی روح پھونکنے کے لیے کیں۔ اس حوالے سے ہم نے لکھا تھا:
’’عام انسانوں کی بات بے شک مختلف ہو گی، مگر مولانا محترم جیسے اہلِ علم سے ہماری توقع یہی ہے کہ وہ اہلِ علم کے عمل سے شریعت اخذ کرنے کے بجائے، شریعت کی روشنی میں اس عمل کا جائزہ لیں۔ اگر شریعتِ اسلامی کے بنیادی ماخذوں، یعنی قرآن و سنت، میں اس عمل کی بنیاد موجود ہے تو اسے شریعت کے مطابق اور اگر ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو بغیر کسی تردد کے اسے شریعت سے ہٹا ہوا قرار دیں۔‘‘
مولانا محترم اس بات کے جواب میں لکھتے ہیں:
’’میرے نزدیک ہمارے درمیان نقطۂ نظر کے اختلاف کا نکتہ اور اصل موڑ یہی ہے۔ یہ اگر واضح ہو جائے تو باقی معاملات کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔‘‘ (روزنامہ اوصاف ، ۱۵ مارچ ۲۰۰۱ء)
اس ضمن میں اپنے نقطۂ نظر کا خلاصہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:
- ’’قرآن و سنت کے بیان کردہ قطعی اور صریح اصولوں کو ہر چیز پر فوقیت اور بالاتری حاصل ہے۔
- جو اصول اہلِ علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں خود مستنبط کیے ہیں ان میں اصل مدار شخصیات پر ہے اور شخصیات کی باہمی ترجیحات ان کے وضع کردہ اصولوں میں بھی کارفرما ہوں گی۔
- ظنی اور استنباطی اصولوں اور سوسائٹی میں ان کے اطلاق و تطبیق کی عملی مشکلات، دونوں کو سامنے رکھ کر احکام و ضوابط طے کیے جائیں گے۔
- بعد میں پیش آنے والی ضروریات کے لیے وضع کیے جانے والے اصولوں کا مؤثر بہ ماضی اطلاق ضروری نہیں ہو گا، اور نہ ہی ماضی کے معاملات کا ان کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔
- صحابہ کرام رضی اللہ عنھم کا دور چونکہ ان سب استنباطات، استدلالات اور اجتہادات سے مقدم ہے اور وہ چشمۂ نبوت سے براہِ راست فیضیاب ہوتے ہیں، اس لیے قرآن و سنت کے مفہوم و مصداق کے تعین اور بعد میں آنے والے اصولوں کے تعارض و تضاد کے حل کے لیے ان کا تعامل حتمی حجت ہے۔‘‘ (روزنامہ اوصاف، ۱۶ مارچ ۲۰۰۱ء)
مولانا محترم نے اگرچہ اسی نکتے کو ہمارے مابین نقطۂ نظر کے اختلاف کا ‘بنیادی موڑ‘ قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے چونکہ اپنے مضمون میں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استدلال پر تبصرہ اور اپنی رائے کے حق میں استدلال بھی پیش فرمایا ہے، اس وجہ سے فی الحال ہم اس نکتے سے تعرض نہیں کریں گے۔ مولانا محترم فی الواقع، اگر مذکورہ بنیاد ہی پر زیربحث رائے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر انہیں قرآن و سنت سے ہمارے استدلال پر نہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اپنی رائے کے حق میں کوئی دلیل پیش کرنے کی۔ اس صورت میں تو انہیں قرآن مجید اور اللہ کے پیغمبروں کی زندگیوں سے ہمارے حوالوں کے جواب میں اور اپنی رائے کی دلیل کے طور پر ’شخصیات‘ کی پیروی کی تلقین کا درس دیتے رہنے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتے، تو ہم یقیناً ’شخصیات‘ کی آرا، ان کے استنباط اور استدلال کے بارے میں مولانا محترم کے فرمودات کا تفصیلی جائزہ قارئین کے سامنے پیش کر دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس وجہ سے، فی الحال خواہ مخواہ کی طوالت اور غیر متعلق مباحث میں الجھنے کے بجائے، ہم مولانا کے ان فرمودات کا جائزہ پیش کر رہے ہیں جو مسئلہ زیر بحث سے براہِ راست تعلق رکھتے ہیں۔
مولانا محترم ہمارے پیش کردہ نکات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’انہوں نے جواب میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے ان کے بقول مسلمانوں کی آبادی پر کافروں کے تسلط کی صورت میں دو ہی راستے بتائے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ اگر ہجرت کا راستہ اور مقام موجود ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہجرت قابل عمل نہ ہو تو صبر و شکر کر کے بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ انہوں نے اس سلسلہ میں سورۃ النساء، سورۃ الانفال اور سورۃ الاعراف کی بعض آیات کریمہ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ وہ مسئلہ کی نوعیت ہی کو سرے سے نہیں سمجھ سکے۔ کیونکہ ان آیات کریمہ میں ان مسلمانوں کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں جو کافروں کی سوسائٹی میں مسلمان ہوگئے ہیں اور ان کے زیر اثر رہ رہے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں تو نکل جائیں ورنہ صبر و حوصلہ کے کے ساتھ حالات کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ جبکہ ہم جس صورت پر بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی پر باہر سے آکر کافروں نے تسلط جما لیا ہے اور مسلمان اکثریت پر کافر اقلیت کا جبر و اقتدار قائم ہوگیا ہے اس صورت میں محترم غامدی اور ان کے تلامذہ ہی مسلم اکثریت کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا علاقہ کافر غالبین کے حوالہ کر کے وہاں سے چلے جائیں یا ان کے جبر و ظلم کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے جائیں۔‘‘ (روزنامہ اوصاف، ۱۶ مارچ ۲۰۰۱)
سب سے پہلے تو ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جسے مولانا محترم نے ’’دو ہی راستے‘‘ قرار دیا ہے، وہ درحقیقت دو نہیں، بلکہ دو سے زیادہ راستے ہیں۔ یہاں ان راستوں کے ذکر کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیرنظر مضمون کے آغاز میں ہم اپنی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے ان راستوں کا ذکر کر چکے ہیں، وہاں ان پر نظر ڈال لیجیے۔
دوسری بات یہ کہ مولانا محترم کی اس توضیح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کسی غیر مسلم آبادی میں کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان پر ان صورتوں کا اطلاق ہو گا جو ہم نے اپنے مضمون میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اب ہمارے اور مولانا کے درمیان اختلاف صرف اس صورت سے متعلق باقی رہ گیا ہے جب کسی بیرونی قوت کی طرف سے مسلمانوں پر یلغار کی گئی ہو اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومت بالکل مفلوج یا ناپید ہو کر رہ جائے۔ ہم یہ بات، البتہ بالکل نہیں سمجھ پائے کہ جبر و استبداد خواہ اپنی غیر مسلم حکومت کی طرف سے ہو یا مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لینے والی حکومت کی طرف سے، دونوں صورتوں میں، دینی لحاظ سے وہ کون سا فرق واقع ہوتا ہے جس کے باعث ان دونوں صورتوں کے دینی احکام میں تفاوت ہو گا۔ معاملہ اگر دینی جبر و استبداد اور ظلم و عدوان ہی کے خلاف لڑنے کا ہے تو وہ تو دونوں صورتوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، معاملہ اگر قومی و ملی حمیت کا ہے تو پھر اس صورتحال میں اور قبطیوں کے آل یعقوب (بنی اسرائیل) کو من حیث القوم اپنا غلام بنا لینے کی صورت میں وہ کون سا فرق ہے جس کے باعث حضرت موسٰی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو قبطیوں کے خلاف جہاد کی نعمتِ عظمٰی کا درس نہیں دیا؟
تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے مضمون میں صرف سورہ نساء، سورہ اعراف، اور سورہ انفال کی آیتوں ہی کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کی سیرت سے بھی استدلال کیا تھا۔ ان پیغمبروں میں سے ایک حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ قارئین پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے وقت فلسطین پر رومیوں کا جابرانہ تسلط قائم تھا۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے لیے رومی ایک غاصب قوم ہی تھے جنہوں نے باہر سے حملہ آور ہو کر ان کی آزادی چھین لی اور انہیں من حیث القوم اپنا مطیع و فرماں بردار بنا لیا تھا۔ اس صورت حال میں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی۔ مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پر بھی اپنی قوم میں ’جہاد‘ کی روح پھونکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں قارئین کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان ہی نہیں لائے، اس وجہ سے آپ کو رومی غاصبوں کے خلاف جہاد و قتال کی روح پھونکنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہمارے نزدیک، بات صرف یہی نہیں ہے کہ حضرت مسیح نے بنی اسرائیل کو اپنے غاصب حکمرانوں کے خلاف جہاد و قتال کا درس نہیں دیا، بلکہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ان سے کھلے کھلے الفاظ میں ان حکمرانوں اور ان کی طرف سے بنی اسرائیل پر خراج عائد کرنے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو آپ نے اس موقع پر بھی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی جس میں ان غاصبوں کے خلاف تلوار اٹھانے یا ان کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب پائی جاتی ہو۔ متی کی انجیل میں یہ واقعہ اس طرح سے نقل ہوا ہے:
’’اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے (یعنی مسیح علیہ السلام کو) کیونکر باتوں میں پھنسائیں۔ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں (یعنی حکمران کے لوگوں) کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پروا نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرف دار نہیں۔ پس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ ایک دینار اس کے پاس لائے۔ اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا قیصر کا۔ اس پر اس نے ان سے کہا پس جو قیصر کا ہے، قیصر کو اور جو خدا کا ہے، خدا کو ادا کرو۔‘‘ (متی باب ۲۲ ، ۱۵ ۔ ۲۲)
حضرت مسیح علیہ السلام کے جواب پر غور کیجیے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس جواب کی اصل روح یہ ہے کہ جب حکومت قیصر کی قائم ہے اور جب سکہ اسی کے نام کا چلتا ہے تو پھر خراج بھی اسی کو ادا کرنا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ غاصب قوم کے خلاف تلوار اٹھانا اگر ’جہاد‘ ہوتا تو حضرت مسیح علیہ السلام، کم از کم اسی موقع پر اللہ کے دین کا یہ تقاضا ضرور بیان فرما دیتے۔
ہمیں مولانا کی اس بات سے پوری طرح اتفاق ہے کہ نساء، اعراف اور انفال کی وہ آیتیں جن کا ہم نے اپنے مضمون میں حوالہ دیا ہے، ان کا تعلق اصلاً اسی صورت حال سے ہے جب کافروں کی کسی بستی میں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں اور اس کے نتیجے میں انہیں حکمرانوں کی طرف سے جبر و استبداد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہوں۔ مگر ہمارے نزدیک، یہ صورت حال دینی و اخلاقی لحاظ سے اس سے کچھ مختلف نہیں ہے کہ جہاں کوئی غیر مسلم قوم کسی مسلمان بستی پر قابض ہو گئی اور اس کو اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے مضمون میں ان آیات کو بنائے استدلال بنایا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت موسٰی اور حضرت مسیح علیہما السلام کے حالات و واقعات سے بھی غیر قوم کے استیلا کے حوالے سے دین و شریعت کے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ ہماری محولہ آیات کے عین مطابق ہیں۔
اس کے بعد مولانا محترم فرماتے ہیں:
’’ہمیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے برعکس رہنمائی ملتی ہے۔
یمن کا علاقہ جناب نبی اکرمؐ کے دور میں مسلم مملکت میں شامل ہوگیا تھا اور شہر بن باذانؓ کو رسول اللہؐ نے اپنی طرف سے وہاں کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ یمن کے مختلف علاقوں میں حضرت علیؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، اور دوسرے عمال کا تقرر کیا تھا۔ مگر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر کے صنعا پر چڑھائی کی اور شہر بن باذانؓ کو قتل کر کے یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ مقتول گورنر کی بیوی کو زبردست اپنے حرم میں داخل کیا، یمن کے مختلف علاقوں سے جناب نبی اکرمؐ کے مقرر کردہ عاملوں کو نکال دیا، اور اس طرح یمن کا صوبہ اسلامی حکومت سے نکل کر کافروں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس پر تین حضرات حضرت فیروز دیلمیؓ، حضرت قیس بن مکشوحؓ، اور حضرت دادویہؓ نے باہمی مشورہ کر کے گوریلا طرز جنگ پر شبخون مارنے کا پروگرام بنایا۔ مقتول مسلمان گورنر شہر بن باذانؓ کی بیوی سے جو اسود عنسی نے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر رکھی تھی، ان تینوں حضرات نے رابطہ کر کے ساز باز کی جس کے تحت اس نے رات کو اسود عنسی کو بہت زیادہ شراب پلا دی، ان حضرات نے محل کی دیوار میں نقب لگا کر اندر داخل ہونے کا راستہ نکالا اور رات کی تاریکی میں اسود عنسی اور اس کے پہرہ داروں کو قتل کر کے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ یہ گوریلا کاروائی تھی اور مسلح کاروائی تھی۔ اس میں معز امجد صاحب کو یقیناً کچھ اخلاقی خرابیاں نظر آرہی ہوں گی اور بلا ضرورت قتل و غارت بھی دکھائی دیتی ہوگی۔ لیکن عملاً یہ سب کچھ ہوا جس کے نتیجہ میں یمن پر مسلمانوں کا اقتدار دوبارہ بحال ہوا ۔ اور جناب نبی اکرمؐ کو جب ان کے وصال سے صرف دو روز قبل وحی کے ذریعہ اس کارروائی کی خبر ملی تو آپؐ نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کرامؓ کو یہ خوشخبری سنائی فاز فیروز کہ فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہوگیا ہے۔ اس کے بعد حضرت فیروز دیلمیؓ جب اس کامیابی کی خبر لے کر یمن سے مدینہ منورہ پہنچے تو جناب نبی اکرمؐ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رپورٹ خلیفۂ اول حضرت صدیق اکبرؓ کو پیش کی اور انہوں نے اس پر اطمینان اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ اس لیے محترم معز امجد صاحب سے عرض ہے کہ جن آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان کا مصداق یہ نہیں ہے بلکہ اس کی عملی شکل وہی یمن والی ہے کہ جب کسی مسلمان ملک پر کافروں کا تسلط قائم ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو صورت بھی اس وقت کے حالات کی روشنی میں اختیار کر سکیں اس سے گریز نہ کریں۔ اور وہ کافر و ظالم قوت کے جابرانہ تسلط کے خلاف مزاحمت کی جو صورت بھی اختیار کریں گے وہ حضرت فیروز دیلمیؓ کی اس گوریلا کاروائی اور شبخون کی طرح جہاد ہی کہلائے گی۔ (روزنامہ اوصاف، ۱۶ مارچ ۲۰۰۲)
یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ واقعہ بعینہ اسی طرح سے ہوا جیسا کہ مولانا محترم نے بیان فرمایا ہے، تب بھی یہ جابر و غاصب قوم کے خلاف گروہ بندی اور جتھا بندی کر کے ’جہاد‘ کرنے کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک غاصب حکمران کے قتل کا واقعہ ہے۔ گروہ بندی اور جتھابندی کر کے جہاد کرنا اور کسی (اچھے یا برے) حکمران کے قتل کی سازش کرنا دو بالکل الگ معاملات ہیں۔ ایک صورت ان ہمہ گیر اخلاقی خرابیوں کا باعث بنتی ہے جن کی طرف ہم نے اپنے پچھلے مضمون میں اشارہ کیا تھا، جبکہ دوسری صورت میں وہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ معاملہ یوں نہیں ہوا کہ ان تین مذکورہ لوگوں نے صنعاء اور یمن کے مسلمانوں کو غاصب قوم کے خلاف منظم کرنے کی جدوجہد کی ہو، بلکہ جیسا کہ مولانا محترم نے بیان فرمایا، معاملہ تو یوں ہے کہ ان تینوں حضرات نے غاصب حکمران کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قتل کے کسی منصوبے کا آخر جہاد سے کیا تعلق ہے؟
مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے رونما ہوا ہی نہیں جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر، ’’اصابہ‘‘ کے مطابق:
بعث النبی الی جشیش و الی دادویہ والی فیروز الدیلمی یامرھم بمحاربۃ الاسود العنسی (ج ۱ ص ۵۳۵)
’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشیش، دادویہ اور فیروز دیلمی کو ایک پیغام بھیجا جس میں آپ نے انہیں اسود عنسی کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا۔‘‘
تاریخ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کارروائی ایک صوبے میں بغاوت کا قلع قمع کرنے کے لیے ایک منظم ریاست ہی کی طرف سے کی گئی تھی، اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اسلامی حکومت نے اپنے تین ایجنٹوں کے ذریعے سے ایک صوبے میں رونما ہونے والی بغاوت کا خاتمہ کرایا۔
ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، ان کے بیان کے چند اہم نکات حسبِ ذیل ہیں:
- اسود عنسی نے نبوت کا دعوٰی کر کے اپنے سات سو ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے نجران پر قبضہ کیا اس کے بعد صنعاء کا قصد کیا اور وہاں کے عامل شہر بن باذام کو قتل کر کے اس پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو اس وقت یمن ہی میں تھے، وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں وہ ابو موسٰی اشعری رضی اللہ عنہ سے ملے اور وہ دونوں حضرموت کی طرف چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال طاہر تک پسپا ہو گئے اور ان میں سے عمر بن حرام اور خالد بن سعید بن عاص مدینہ لوٹ آئے۔
- اسود عنسی کی حکومت پوری طرح سے مستحکم ہو گئی۔ اس وقت اس کی فوج میں سات سو گھڑسوار شامل تھے۔ اس کی فوج کے امرا کے نام یہ ہیں: قیس بن عبد یغوث (یہ قیس بن مکشوح ہی ہیں)، معاویہ بن قیس، یزید بن محرم بن حصن حارثی اور یزید بن افکل ازدی۔
- اسود کی حکومت کے زور پکڑنے کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہونے لگے۔ ان مرتدین میں، بظاہر مسلمان عمال بھی شامل تھے۔
- اس نے قیس بن عبد یغوث کو اپنا امیر الجند اور فیروز دیلمی اور دادویہ کو ابنا کے معاملے کا ذمہ دار بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے شہر بن باذام کی بیوہ سے، جس کا نام زاذ تھا اور جو فیروز دیلمی کی چچازاد تھی، شادی کر لی۔ زاذ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مومن و صالح عورت تھی۔
- جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کی بغاوت کی خبر ملی تو آپؐ نے وبر بن یحنس دیلمی کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو اسود عنسی کے خلاف جنگ کرنے اور اس پر حملہ کرنے کا حکم دیا جو وہاں موجود تھے۔
- معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کے لیے پوری طرح سے کمربستہ ہو گئے۔ سکون کے لوگ جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سسرالی رشتے دار تھے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ان تمام عمال اور مسلمانوں تک پہنچا دیا جن تک پہنچنا ان کے لیے ممکن تھا۔
- مسلمانوں کے اجتماع نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ کام قیس بن عبد یغوث کے ذریعے سے کرایا جائے کیونکہ اسے اسود عنسی پر بہت غصہ تھا اور وہ اسے حقیر جانتا اور اس کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہی معاملہ فیروز دیلمی اور دادویہ کا بھی تھا۔
- چنانچہ جب وبر بن یحنس نے قیس کو اس اسکیم کی خبر دی تو اس کے لیے یہ ایسا ہی تھا گویا اسے آسمان سے ایک موقع مل گیا ہو اور اس طرح انہوں نے اسود عنسی کے قتل کی اسکیم بنائی۔ اس کے بعد قیس نے دادویہ اور فیروز دیلمی کو اپنی اس اسکیم میں شامل کیا۔ بالآخر، ان تینوں حضرات نے اسود عنسی کی بیوی کے ساتھ مل کر اسود کے قتل کے منصوبہ کو روبہ عمل کیا۔
ان نکات سے جو باتیں بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہیں، وہ یہ ہیں:
- اسود عنسی کے خلاف اس کے محکوم و مظلوم عوام نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ وہ بے چارے تو اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے۔
- یہ پوری کارروائی اصلاً مسلمانوں کی منظم ریاست ہی کی طرف سے اپنے ایک صوبے میں ہونے والی بغاوت کے قلع قمع کے لیے کی گئی تھی۔
- اس کارروائی کا عملی ظہور اسود عنسی کے اپنے گروہ میں پھوٹ پڑنے اور اس کے اپنے ہی عمال کی طرف سے اس کے قتل کا کامیاب منصوبہ بنانے کی صورت میں ہوا۔
اب قارئین خود ہی اس بات کا فیصلہ فرمائیں کہ اس کارروائی سے مولانا محترم نے جو استدلال کیا وہ صحیح ہے یا غلط۔
زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس کا جواز
جہاد کے علاوہ مولانا محترم نے ہمارے استاذ کی اس رائے پر بھی اظہار خیال فرمایا تھا کہ
’’زکوٰۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹیکسیشن کو ممنوع قرار دے کر حکمرانوں سے ظلم کا ہتھیار چھین لیا ہے۔‘‘
مولانا محترم نے اپنے مضمون میں اس رائے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا:
’’لیکن کیا کسی ضرورت کے موقع پر (زکوٰۃ کے علاوہ) اور کوئی ٹیکس لگانے کی شرعاً ممانعت ہے؟ اس میں ہمیں اشکال ہے۔ اگر غامدی صاحب محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کے بعد کسی اور ٹیکسیشن کی ممانعت پر کوئی دلیل پیش فرما دیں تو ان کی مہربانی ہو گی اور اس باب میں ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔‘‘
اس کے جواب میں ہم نے اپنی معروضات میں اپنے استاذ کی رائے، انہی کے الفاظ میں، مولانا کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔
روزنامہ ’’اوصاف‘‘ کی ۱۷ مارچ کی اشاعت میں مولانا محترم نے استاذ گرامی کی اس رائے پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ وہ، اب تک کے تبادلۂ خیالات کا خلاصہ اور استاذ گرامی کے استدلال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
’’زکوٰۃ کے بارے میں جناب جاوید غامدی نے فرمایا تھا کہ اسلامی مملکت میں اجتماعی معیشت کے نظام کو چلانے کے لیے زکوٰۃ ہی کا نظام کافی ہے اس کے علاوہ اسلام نے حکومت کو اور کوئی ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ درست ہے کہ اگر زکوٰۃ اور دیگر شرعی واجبات کا نظام صحیح طور پر قائم ہو جائے تو معاشرہ کی اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی درست ہے کہ ٹیکسوں کا مروجہ نظام سراسر ظالمانہ ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وقت قومی ضروریات زکوٰۃ اور بیت المال کی دیگر شرعی مدات سے پوری نہ ہوں تو کیا حکومت وقتی ضرورت کے لیے کوئی اور ٹیکس جائز حد تک لگانے کی مجاز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ممانعت کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل غامدی صاحب کے پاس موجود ہو تو وہ رہنمائی فرمائیں۔
اس کے جواب میں معز امجد صاحب نے قرآن کریم کی بعض آیات اور جناب نبی اکرمؐ کے بعض ارشادات سے استدلال کیا ہے مگر یہ استدلال ان کے موقف کی تائید نہیں کرتا۔ مثلاً انہوں نے سورۃ التوبہ کی آیت ۵ کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کرلیں، نماز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں تو ’فخلوا سبیلہم‘ ان کی راہ چھوڑ دو۔ یہاں ان کی راہ چھوڑ دو سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ان سے اور کوئی مالی تقاضہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ مگر اس کی وضاحت میں مسلم شریف کی جو روایت انہوں نے پیش کی ہے اس میں جناب نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت دے دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جب وہ ایسا کریں تو ان کی جانیں اور ان کے اموال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہاں اموال کے محفوظ ہو جانے کا مفہوم معز امجد صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ ان سے مزید کوئی مالی تقاضہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر ان کے بیان کردہ مفہوم کو صحیح سمجھ لیا جائے تو بھی اس روایت میں ’الا بحقھا‘ کی استثناء موجود ہے جو خود انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ جس سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ اسلام کے حقوق کے حوالہ سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کا تقاضہ مسلمانوں سے کیا جا سکتا ہے۔‘‘ (اوصاف ، ۱۷ مارچ ۲۰۰۱ء)
مولانا محترم کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت کے آخر میں ’’الا بحقھا‘‘ کے الفاظ نے وہ استثنا پیدا کر دیا ہے جس کی بنیاد پر اب حکومت روایت میں مذکور مطالبات کے پورا کر دینے کے باوجود بھی اپنے مسلمان شہریوں پر مزید ذمہ داریاں عائد کر سکتی ہے۔ مولانا محترم کی اس بات کا جائزہ لینے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قارئین کے سامنے سورہ توبہ کی محولہ آیت کا موقع و محل اور اس میں پایا جانے والا زور پوری طرح سے واضح کر دیں اور پھر اس آیت کے حکم کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مذکورہ روایت کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس سے وہ بات کس حد تک نکلتی ہے جو مولانا محترم نے اس سے نکالی ہے۔
سورہ توبہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمامِ حجت کے بعد، جزیرہ نماے عرب سے مشرکین کے خاتمے کا حکم نازل ہوا ہے۔ اسی حکم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح فرما دی گئی کہ اب ان مشرکین کو زندگی کی مہلت صرف اسی صورت میں حاصل رہے گی کہ اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ سورہ کی آیت ۵ میں ان مشرکین کی جان بخشی کی شرائط بیان ہوئی ہیں۔ ان میں اسلام کے خلاف عقائد سے توبہ کرنے، نماز کا اہتمام کرنے اور ریاست کے بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرنے کی شرائط شامل ہیں۔ اس کے بعد مسلمان ریاست کو یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے اگر یہ تقاضے پورے کر دیے جائیں، تو پھر ان کی راہ چھوڑ دو۔ بالفاظِ دیگر اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمامِ حجت کے بعد اب اس سرزمین پر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق صرف انہی کا ہے جو اس پیغمبر پر ایمان لے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ وہ کون کون سے مطالبات ہیں جو ایک شخص کو مومن و مسلم سمجھنے کے لیے ریاست ان سے کر سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک ’فخلوا سبیلھم‘ کا پورا زور سمجھنے کے لیے یہ بات پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ اس آیت میں مسلمان ریاست کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مسلمانوں کے حقوق دینے کے لیے ان سے کون کون سے مطالبات کر سکتی ہے۔ اس صورت میں مولانا محترم ہی ہمیں سمجھائیں کہ ’فخلوا سبیلھم‘ کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ مذکورہ مطالبات کو پورا کر دینے کے بعد، ان کے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہ ڈالو، ان پر مزید کوئی بوجھ نہ ڈالو اور انہیں وہ تمام حقوق دینے کے لیے جو ایک اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے انہیں حاصل ہونے چاہئیں، ان سے مزید کوئی تقاضا نہ کرو۔ اس حکم کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ ایک اسلامی ریاست کے لیے اپنے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس عائد کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، بلکہ قانونی و اخلاقی منکرات سے اجتناب کو چھوڑ کر، ان پر کسی بھی قسم کی کوئی مزید قانونی ذمہ داری عائد کرنے کی راہ بھی مسدود ہو جاتی ہے۔
آیت کا یہ مفہوم بالکل واضح ہے۔ مولانا محترم کے نزدیک، مذکورہ آیت کے اگر وہ معنی نہیں ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر آیت کے الفاظ اور اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں ہماری غلطی ہم پر واضح فرما دیں۔
اس آیت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مذکورہ روایت کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے وہ معنی کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے جو مولانا محترم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت میں روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے، وہ قرآنِ مجید کے خلاف قرار پائے گی اور اس وجہ سے، اس روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کسی طرح بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ مجید کے واضح حکم کے خلاف کوئی بات ارشاد فرمائیں۔
حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ روایت میں ’الا بحقھا‘ کے الفاظ میں جو استثنا بیان ہوا ہے، اس کے وہ معنی ہی نہیں ہیں جو مولانا محترم نے بیان فرمائے ہیں۔ ’الا بحقھا‘ کے معنی اگر وہ ہیں جو مولانا محترم نے بیان فرمائے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ روایت قرآن مجید کے واضح حکم کے خلاف قرار پاتی ہے، بلکہ خود اس روایت میں بھی جو بات بیان ہوئی ہے، وہ بھی بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس پوری روایت پر ایک مرتبہ پھر سے نظر ڈال لیجیے۔ اس روایت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
امرت ان اقاتل الناس حتی یشھدوا ان لا الٰہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلٰوۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا عصموا منی دمائھم واموالھم الا بحقھا وحسابھم علی اللہ۔ (مسلم، کتاب الایمان)
’’مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ شرائط پوری کر دیں تو ان کی جانیں اور ان کے اموال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس سے محروم کر دیے جائیں۔ رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔‘‘
غور کیجئے ’الا بحقھا‘ کے معنی فی الواقع وہی ہوں جو مولانا محترم بیان فرما رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جان و مال کو جو اپنی امان دی ہے، وہ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اس صورت میں پوری بات کچھ یوں ہو جائے گی کہ ’’لوگوں کی جان و مال کی حرمت اس وقت تک کے لیے ختم ہو گئی ہے، جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار نہ کر لیں اور نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے جان و مال مجھ سے مامون ہو جائیں گے، الا یہ کہ ان پر کوئی خراج عائد کروں (یا کسی مقصد سے ان کی جان لینے کا فیصلہ کروں)۔‘‘
ظاہر ہے کہ ’الا بحقھا‘ کے استثنا کے اگر یہ معنی ہیں، جیسا کہ مولانا محترم نے بیان فرمایا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان و مال کو ایمان لانے، نماز و زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی کوئی امان حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ عربیت کی رو سے ’الا بحقھا‘ میں جو استثنا بیان ہوا ہے، اس میں صرف مال کی حرمت کا استثنا نہیں، بلکہ جان کی حرمت کا استثنا بھی شامل ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح شریعت ہی کا کوئی حق قائم ہوئے بغیر ریاست اپنے کسی شہری کی جان نہیں لے سکتی، بالکل اسی طرح شریعت ہی کا کوئی حق قائم ہوئے بغیر، وہ اپنے کسی شہری کے مال کی حرمت کو بھی پامال نہیں کر سکتی۔ یہی وہ بات ہے جو زیرغور روایت میں بیان ہوئی ہے۔ ’الا بحقھا‘ کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ’’سوائے اس صورت میں کہ (شریعت ہی کے) کسی حق کے تحت وہ ان (یعنی جان و مال) سے محروم کر دیے جائیں‘‘۔
ابو طیب ’’عون المعبود‘‘ میں لکھتے ہیں:
الا بحقھا ای الدماء والاموال، الباء بمعنی عن۔ یعنی ھی معصومۃ الا عن حق اللہ۔ (باب علی ما یقاتل المشرکون، ج ۷ ص ۲۱۶)
’’’الابحقھا‘ سے مراد جان اور مال پر حق کا قائم ہونا ہے۔ یہاں ’باء‘ ، ’عن‘ کے معنی میں ہے۔ یعنی یہ دونوں مامون ہیں سوائے اس کے کہ ان پر اللہ ہی کا (بیان کردہ) کوئی حق قائم ہو جائے۔‘‘
عبد الرحمٰن مبارک پوری رحمہ اللہ ’’سنن ترمذی‘‘ کی شرح ’’تحفۃ الاحوذی‘‘ میں لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ
’’اسلام میں داخل ہو جانے اور نماز کے قائم اور زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد لوگوں کا خون بہانا اور ان کے اموال کو کسی بھی سبب سے مباح کرنا ناجائز ہے، سوائے اس کے اسلام ہی کا کوئی حق ان کے جان و مال پر قائم ہو جائے۔ مثال کے طور پر، قصاص کے قانون کے تحت کسی کی جان لینا یا کسی سے غصب شدہ مال واپس لینا۔‘‘
یہی بات مناوی رحمہ اللہ نے ’’فیض القدیر‘‘ میں بھی لکھی ہے:
اسی طرح ابو الفرج حنبلی اپنی کتاب ’’جامع العلوم والحکم‘‘ میں ’الابحقھا‘ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
ومن حقھا الا متناع عن الصلاۃ والزکاۃ بعد الدخول فی الاسلام کما فھمہ الصحابۃ رضی اللہ عنھم۔ (ج ۱ ص ۸۵)
’’اور وہ حقوق جو ان پر قائم ہوتے ہیں، ان میں اسلام لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار ہے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے فہم سے واضح ہے۔‘‘
اس ساری تفصیل سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے ’الابحقھا‘ کے وہ معنی کسی طرح بھی نہیں لیے جا سکتے جو مولانا محترم بیان فرما رہے ہیں۔
اس کے بعد مولانا محترم لکھتے ہیں:
’’پھر انہوں نے ابن ماجہ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی حق عائد نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ترمذی کے حوالے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کر دیا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ آیات اور روایات غامدی صاحب کے موقف کے بجائے ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں کہ ضرورت پڑنے پر زکوٰۃ کے علاوہ مزید ٹیکس بھی اسلامی حکومت کی طرف سے عائد کیا جا سکتا ہے۔‘‘ (اوصاف، ۱۷ مارچ ۲۰۰۱ء)
مولانا محترم کی یہ بات پڑھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری معروضات کو اپنی توجہ کے لائق نہیں سمجھا۔ ہم نے اپنے مضمون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ دو بظاہر متناقض فرمان ہی نقل نہیں کیے، بلکہ ان کے باہمی تناقض کو حل کرنے کے لیے ان کا الگ الگ محل بھی واضح کیا ہے۔ یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان روایتوں کو ہم نے جس محل میں سمجھا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مولانا محترم کی نظر میں درست نہ ہو، لیکن معاملہ اگر فی الواقع یہی ہے تو پھر مولانا سے ہماری گزارش ہے کہ وہ، کم از کم ان دونوں روایتوں کا صحیح محل ہی واضح فرما دیں جس سے ان کے باہمی تناقض کو حل کرنے کی کوئی راہ کھل جائے۔ اس وضاحت کے بغیر، مولانا محترم اگر محض یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں کہ ’’نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی حق عائد نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے‘‘۔ تو پھر یقیناً قارئین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ کیا مولانا محترم اس بات کے قائل ہیں کہ مختلف موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہم متناقض تعلیمات ارشاد فرماتے تھے، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ان دونوں ارشادات کے محل بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک میں آپ نے حکومت کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے اموال میں زکوٰۃ کے بعد حکومت کا کوئی اور حق قائم نہیں ہوتا، جبکہ دوسری روایت میں آپؐ نے قرابت مندوں، غرباء، مساکین اور معاشرے کے اہل حاجت کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد بھی مسلمانوں کے اموال میں ان لوگوں کی مالی امداد کرنے کا حق قائم ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، حکومت تو اگرچہ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں سے جبری طور پر کچھ وصول کرنے کا حق نہیں رکھتی، تاہم مسلمانوں پر اجتماعی و انفرادی ضروریات کے لیے خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کے بعد بھی قائم ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ’’فتح الباری‘‘ میں اس سے ملتی جلتی بات اس طرح سے واضح کی ہے:
وفیہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ واجاب العلماء عنہ بجوابین: احدھما ان ھذا الوعید کان قبل فرض الزکاۃ و یؤیدہ ما سیاتی من حدیث بن عمر فی الکنز ولکن یعکر علیہ ان فرض الزکاۃ متقدم علی اسلام ابی ھریرۃ کما تقدم تقریرہ۔ ثانی الاجوبۃ ان المراد بالحق القدر الزائد علی الواجب ولا عقاب یترکہ وانما ذکر استطرادا لما ذکر حقھا بین الکمال فیہ وان کان لہ اصل یزول الذم یفعلہ وھو الزکاۃ۔ (ج ۳ ص ۲۶۹)
’’اور اس میں یہ بھی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق قائم ہوتا ہے۔ علما نے اس (باہمی تناقض) کے دو طرح سے جواب دیے ہیں: ایک یہ کہ یہ بات زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے فرمائی گئی ہو گی۔ کنز کے بارے میں ابن عمر کی روایت جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، اس توجیہ کی تائید کرتی ہے، مگر اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت حضرت ابوہریرہ کے اسلام لانے سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں ’حق‘ سے مراد وہ اضافی مقدار ہے جو زکوٰۃ واجب کے ادا کر دینے کے بعد دی جائے جس کے نہ ادا کرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ اس کا ذکر اس معاملے میں درجۂ کمال کی تعلیم کے حوالے سے کیا گیا ہے، اگرچہ وہ ادائیگی جس کے بعد حقِ واجب مکمل طور پر پورا ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ہی ہے۔‘‘
جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، اس ’اضافی حق‘ کی مثال وہ خرچ ہے جو کوئی شخص کسی اجتماعی یا انفرادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں، غزوات کے موقعوں پر ان کا خرچ اسی مد میں آئے گا۔ یہ معلوم ہے کہ ریاستِ مدینہ میں مسلمانوں سے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب کسی اجتماعی ضرورت کے لیے پیسا جمع کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اس مقصد کے لیے ریاست کی طرف سے اپیل کی جاتی تھی جس پر مسلمان دل کھول کر اپنی جمع پونجی لٹا دیتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ریاستِ مدینہ کو بارہا ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی ضرورتیں پوری کرنی مشکل ہو گئیں، مگر ایسے حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا، بلکہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مسلمانوں سے اپنی مقدور بھر اعانت کرنے کی اپیل کی۔ یہ واقعات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ ’’اگر کسی وقت قومی ضروریات زکوٰۃ اور بیت المال کی دیگر شرعی مدات سے پوری نہ ہوں‘‘، جیسا کہ مولانا نے یہ سوال اٹھایا ہے، تب بھی ریاست اپنے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے مالی اعانت کی اپیل کرے۔ اس طرح کی کسی قومی ایمرجنسی میں ریاستی اپیل کے جواب میں قرآن مجید مسلمانوں کو ’العفو‘ یعنی ان کے پاس اپنی ضروریات سے بڑھ کر جو کچھ ہو، وہ سب خرچ کر دینے کی ہدایت کرتا ہے۔
اس کے بعد مولانا محترم نے مولانا مناظر احسن گیلانی اور مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی رحمہما اللہ کے حوالے سے امت کے بعض جلیل القدر بزرگوں کی یہ رائے نقل کی ہے کہ:
’’اجتماعی ضروریات مثلاً نہر کھودنے، دفاعی تیاریوں، فوج کی تنخواہ، اور قید کی رہائی وغیرہ کے لیے مزید ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں۔ البتہ، ہنرمندوں اور کاروباری لوگوں پر ان کے ہنر یا کاروبار کے حوالے سے جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ ظالمانہ ہیں اور شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔‘‘ (اوصاف، ۱۷ مارچ ۲۰۰۱ء)
اوپر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دین کے ان اصل ماخذوں سے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس عائد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد کسی شخص کی بات یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ اسے ان آیات و ارشادات سے نکلنے والے حکم پر ترجیح دی جائے۔ اس وجہ سے مولانا محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے تو ہمارے استدلال کی کمزوری ہم پر واضح فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی مذکورہ آیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محولہ ارشادات سے مسلمانوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کرنے کی حرمت اگر ثابت نہیں ہوتی تو مولانا کو ٹیکس کے جواز کا استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر دین و شریعت میں واضح طور پر ٹیکس عائد کرنے کے خلاف کوئی حکم موجود نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں، آپ سے آپ زکوٰۃ کے علاوہ مزید ٹیکس لگانا جائز قرار پائے گا۔ مولانا محترم کو اس کے جواز کے لیے کسی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہو گی۔ اس وجہ سے مولانا محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ لوگوں کی آرا کا حوالہ دینے کے بجائے، ہمارے استدلال کی غلطی واضح فرما دیں، اس کے نتیجے میں ان کی رائے آپ سے آپ صائب قرار پا جائے گی۔
مولانا محترم مزید لکھتے ہیں:
’’۔۔۔ اصولی طور پر قومی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ اسلامی حکومت جائز حد تک اور ٹیکس بھی لگا سکتی ہے اور اس کی کوئی واضح شرعی ممانعت موجود نہیں ہے۔‘‘ (اوصاف، ۱۶ مارچ ۲۰۰۱ء)
ہمارے نزدیک وہ ’’جائز حد‘‘ جس تک حکومت کو اپنے مسلمان شہریوں سے ٹیکس لینے کا حق حاصل ہے، وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ مولانا محترم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر، فی الواقع حکومت کے پاس اپنے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی ٹیکس عائد کرنے کا اختیار موجود ہوتا تو پھر اموال، مواشی اور پیداوار وغیرہ پر زکوٰۃ کی زیادہ سے زیادہ شروح متعین کرنے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مختلف صورتوں پر زکوٰۃ کی زیادہ سے زیادہ شروح کی تعیین کرنے کا اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھوں، ٹیکس کے ذریعے سے ہونے والے لوگوں کے استحصال کے خلاف پیش بندی کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس عائد کرنے کی گنجائش موجود ہوتی تو پھر زکوٰۃ کی زیادہ سے زیادہ شروح متعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخر زکوٰۃ کی متعین شروح میں اضافہ کرنے یا کوئی نیا ٹیکس عائد کرنے میں وہ کون سا فرق ہے جس کے باعث ایک جائز اور ایک ناجائز ٹھہرتا ہے؟ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اسی حکمت کو واضح کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن انس رضی اللہ عنہ کو مختلف صورتوں پر عائد ہونے والی زکوٰۃ کی شروح واضح کرتے ہوئے یہ ہدایت بھیجی تھی:
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ھذا فریضۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتی امر اللہ بھا رسولہ فمن سئلھا من المسلمین علی وجھھا فلیعطھا و من سئل فوقھا فلا یعط۔ (بخاری، رقم ۱۳۶۲)
’’بسم اللہ الرحمٰن الرحیم، صدقات کے معاملے میں یہ وہ فریضہ ہے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر لازم ٹھہرایا اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا۔ چنانچہ مسلمانوں سے جب اس کے مطابق مانگا جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے ادا کر دیں اور جب ان سے اس سے زیادہ مانگا جائے تو پھر وہ نہ دیں۔‘‘
اسی طرح جب انہوں نے مانعینِ زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تو لوگوں کے معارضہ پر یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ اس طرح واضح فرمائی:
قال اللہ تعالیٰ، فان تابوا واقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ فخلوا سبیلھم، واللہ، ولا اسئل فوقھن ولا اقصر دونھن۔ (احکام القرآن للجصاص ، ج ۲ ص ۸۲)
’’اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، (اس لیے) خدا کی قسم، میں ان شرطوں پر کسی اضافے کا مطالبہ کروں گا اور نہ ان میں کوئی کمی برداشت کروں گا۔‘‘
اسی طرح، حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب ان کے بعض عمال نے یہ لکھا کہ لوگوں کے مسلمان ہونے سے چونکہ حکومت کی وصولی میں کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے لوگوں سے مسلمان ہونے کے بعد بھی جزیہ وصول کیا جاتا رہے۔ تو انہوں نے ’’جائز حد‘‘ ہی تک صحیح، مسلمانوں پر کوئی اضافی ٹیکس عائد کرنے سے انکار کرتے ہوئے لکھا:
ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم داعیا ولم یبعثہ جابیا فاذا اتاک کتابی ھذا فارفع الجزیۃ عمن اسلم من اھل الذمۃ۔ (احکام القرآن للجصاص ج ۴ ص ۲۹۶)
’’اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی طرف پکارنے والا بنا کر بھیجا تھا، لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ چنانچہ اس خط کے پہنچتے ہی، اسلام قبول کرنے والوں پر سے جزیہ ختم کر دو۔‘‘
شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ’’حجۃ اللہ البالغہ‘‘ میں زکوٰۃ کی شرحیں متعین کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
ثم مست الحاجۃ الی تعیین مقادیر الزکاۃ اذ لو لا التقدیر لفرط المفرط ولاعتدی العتدی۔ ویجب ان تکون غیر یسیرۃ لا یجدون بہ بالا ولا تنجع من بخلھم ولا ثقیلۃ یعسر علیھم اداؤھا۔ (جز ۲ ص ۳۹)
’’پھر ضرورت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ مختلف صورتوں کے لیے زکوٰۃ کی مقدار متعین کر دی جائے۔ اگر یہ تعیین نہ کی جاتی تو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کی راہ کھلی رہتی۔ یہ ضروری تھا کہ یہ مقدار نہ اتنی کم ہو کہ لوگ اسے کوئی اہمیت نہ دیں اور نہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کی ادائیگی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔‘‘
زکوٰۃ کی متعین شرحیں ہی وہ ’’جائز حد‘‘ ہے جس تک ایک اسلامی ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے وصولی کر سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ٹیکس لینا ’’ناجائز‘‘ حدود میں داخل ہونا ہی ہے۔ بہرحال، مولانا محترم اگر اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود سے آگے بھی ’’جائز‘‘ و ’’ناجائز‘‘ کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر وہی مہربانی فرما کر یہ واضح فرما دیں کہ اس معاملے میں جائز و ناجائز کا فیصلہ کون کرے گا؟
علما کے فتوے
جہاں تک فتووں کے بارے میں ہمارے اور مولانا محترم کے درمیان اختلاف کا تعلق ہے، اس میں ہمیں افسوس ہے کہ قارئین کو اصطلاحات کی بھول بھلیاں میں الجھا کر خلطِ مبحث پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی بحث ہی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ کس قسم کے فتوے ہیں جنہیں ناجائز قرار پانا چاہیے۔ اس کے جواب میں مولانا محترم نے ’فتوٰی‘، ’امر‘ اور ’قضا‘ کی اصطلاحات کی تفصیل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سے کس کی کیا حیثیت ہے۔
ہم نے اپنے پچھلے مضمون میں یہ واضح کیا ہے کہ جس ’فتوٰی‘ پر ہمیں اعتراض ہے وہ دراصل ’فتوٰی‘ کے نام پر ’قضا‘ کے معاملات ہیں۔ مولانا محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ’فتوٰی‘، ’امر‘ اور ’قضا‘ کا فرق سمجھانے کے بجائے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی مثالوں میں جن ’فتووں‘ کو حدود سے متجاوز قرار دیا ہے، وہ انہیں کس بنیاد پر جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ اگر اس نکتے کو واضح فرمائیں گے تو ہم ان کے فرمودات پر غور کر کے اپنے معروضات پیش کر دیں گے۔ مولانا کی موجودہ غیر متعلق بحث کے بارے میں ہمیں، فی الحال کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
امام ابن تیمیہ، الجزائر کی جنگِ آزادی، اور جہادِ افغانستان
ڈاکٹر محمد فاروق خان
پچھلے کچھ عرصہ سے مولانا زاہد الراشدی صاحب کی تحریروں میں تین حوالے بار بار آ رہے ہیں۔ ایک دمشق پر تاتاریوں کے حملے کے دوران میں امام ابن تیمیہ کا کردار، دوسرے الجزائر کی جنگِ آزادی، اور تیسرے جہادِ افغانستان۔ چنانچہ یہ مناسب ہے کہ درجِ بالا تینوں معاملات کا تاریخی و نظریاتی جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہمارے آج کے حالات میں ان سے کیا کیا سبق ملتے ہیں۔
یہ ۶۹۴ھ کی بات ہے۔ ایران و عراق پر قازان نامی ایک تاتاری حکمران تھا۔ اسی سال اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت شام سلطانِ مصر کے تحت تھا اور وہ اسے اپنے نائب منتظمِ قلعہ کے ذریعے سے کنٹرول کرتا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شام کے دارالحکومت دمشق میں تھے۔ ۶۹۹ھ میں یہ اطلاعات آئیں کہ قازان شام پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگرچہ اس وقت تمام تاتاری مسلمان ہو چکے تھے، تاہم ان کی دہشت انگیزی اور سفاکی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ربیع الاول ۶۹۹ھ میں دمشق سے باہر تاتاری افواج اور سلطانِ مصر کی افواج میں مقابلہ ہوا۔ اس میں سلطانِ مصر کی افواج نے شکست کھائی۔ تاتاری فوجیں شہر میں داخل نہ ہوئیں اور شہر میں بدستور سلطانِ مصر کا نائب موجود رہا۔ البتہ، شہر میں بہت انتشار پھیل گیا اور ہر دم یہ خطرہ رہنے لگا کہ تاتاری افواج آگے بڑھ کر کہیں دمشق میں قتل و غارت کا بازار نہ گرم کر دیں۔ اس موقع پر امام ابن تیمیہؒ نے آگے بڑھ کر سیاسی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک وفد کی صورت میں تاتاریوں کے بادشاہ قازان سے ملاقات کے لیے گئے اور اس کی طرف سے اہلِ دمشق کے لیے پروانۂ امن لے آئے۔ اس کے نتیجے میں دمشق پر تاتاریوں کا پراَمن قبضہ ہو گیا۔ صرف قلعہ سلطانِ مصر کی وفادار افواج کے پاس رہا۔ اس دوران میں امن و امان کے قیام کے لیے امام صاحب تاتاری حکمرانوں سے مسلسل رابطے میں رہے۔
پانچ مہینے کے بعد یعنی رجب ۶۹۹ء میں معلوم ہوا کہ تازہ دم مصری افواج شام کی طرف آ رہی ہیں۔ اگلے ہی دن تاتاریوں نے دمشق خالی کر کے شام سے واپسی اختیار کر لی۔ چونکہ شہر میں اب بھی طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا، اس لیے امام ابن تیمیہؒ نے مصری نائب السلطنت جمال الدین کا پورا پورا ساتھ دیا اور حکومتی اختیار بحال کرنے میں اس کی بھرپور مدد کی۔ چار مہینے بعد دوبارہ اطلاع ملی کہ تاتاری ایک دفعہ پھر حملہ کے لیے پر تول رہے ہیں، چنانچہ اس موقع پر امام صاحب نے نہ صرف نائب السلطنت کو بھرپور تعاون کی پیشکش کی، بلکہ جب انہیں یہ تاثر ملا کہ شاید سلطانِ مصر مقابلہ نہ کرے تو وہ خود مصر گئے اور سلطانِ مصر کو تاتاریوں کے مقابلہ پر آمادہ کیا، چنانچہ تاتاریوں کو حملے کا حوصلہ نہ ہوا۔
رجب ۷۰۲ھ میں ایک دفعہ پھر اطلاع ملی کہ تاتاری حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ تردد پیدا ہوا کہ تاتاری بھی تو، بہرحال مسلمان ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جنگ کی فقہی حیثیت کیا ہے۔ اس موقع پر امام ابن تیمیہؒ نے فتوٰی دیا کہ چونکہ تاتاری جارح اور ظالم ہیں اور وہ ایک پراَمن مسلمان ملک کو تکلیف دینے کے درپے ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ پوری قوت کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ تاتاریوں اور سلطانِ مصر کی افواج میں جنگ ہوئی جس میں سلطانِ مصر کو کامیابی ملی اور یوں ملکِ شام پر سلطانِ مصر کا قبضہ مستحکم ہو گیا۔
درجِ بالا پورے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام ابن تیمیہؒ نے پہلے سے موجود مسلمان حکومت کی پوری پشت پناہی کی اور بوقتِ ضرورت مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے مسلمان دشمن طاقت سے کامیاب مذاکرات بھی کیے۔
اس کے بعد ہم الجزائر کی تحریکِ آزادی اور جنگِ آزادی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ الجزائر پر فرانس نے ۱۸۳۰ء میں حملہ کیا، اس وقت الجزائر عثمانی ترکوں کے تحت تھا۔ تاہم، عمومی طوائف الملوکی تھی اور ملک مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ سید محی الدین الحسنی کی سربراہی میں مختلف ریاستوں نے فرانسیسی حملے کے خلاف مزاحمت کی۔ سید محی الدین کے بعد ان کے بیٹے عبد القادر حاکم مقرر ہوئے۔ حکومتِ فرانس نے دو مرتبہ عبد القادر سے صلح کی اور دونوں دفعہ بدعہدی کی۔ آخرِکار فرانس نے کئی چھوٹے حکمرانوں کو لالچ دے کر خرید لیا اور ۱۸۴۷ء میں امیر کو ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد یہ ملک تقریباً سو سال تک فرانس کے زیرقبضہ رہا۔
۱۹۵۴ء میں محاذ حریتِ وطنی (FLN) کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی۔ یہ الجزائر کے باشندوں کی واحد تنظیم تھی۔ ۱۹۵۸ء میں قاہرہ میں الجزائر کی حکومت قائم کی گئی جس کے صدر فرحت عباس مقرر ہوئے۔ اس آزاد حکومت نے الجزائر کے ان تمام علاقوں کا نظم و نسق سنبھال لیا جہاں فرانسیسی افواج کی گرفت کمزور تھی۔ اسی حکومت اور واحد تنظیم ’’محاذ حریت وطنی‘‘ کے زیرانتظام مسلح جنگ آزادی شروع ہوئی۔ جب فرانس کو اندازہ ہوا کہ اس کے لیے الجزائر کے لوگوں کو دبانا ممکن نہیں ہے تو صدر ڈیگال نے آزاد حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی، اس کے نتیجے میں ایک سمجھوتے کے تحت ۳ جولائی ۱۹۶۲ء کو الجزائر پوری طرح آزاد ہو گیا۔
اس جنگِ آزادی کی کامیابی میں جن عوامل نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، ان میں تمام مقامی باشندوں کا ایک ہی تنظیم کے جھنڈے تلے جمع ہونا، متفقہ آزاد حکومت کا قیام، اس کے تحت آزاد علاقوں کا انتظام و انصرام، اور اسی حکومت کے تحت جہادِ آزادی کا انتظام شامل ہیں۔ اس جدوجہدِ آزادی کے فورًا بعد ایک منظم حکومت نے زمامِ اقتدار سنبھال لی۔
اب ہم افغانستان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جن تنظیموں نے روسی جارح افواج کے خلاف مزاحمت کی، ان میں سب سے پہلی تنظیم ’’جمعیتِ اسلامی‘‘ تھی جو ۱۹۷۲ء میں بنی تھی۔ اس کے صدر برہان الدین ربانی اور سیکرٹری جنرل گلبدین حکمت یار تھے۔ ۱۹۷۹ء میں اس پارٹی میں پھوٹ پڑی اور گلبدین حکمت یار نے اپنی پارٹی ’’حزبِ اسلامی‘‘ کے نام سے بنا لی۔ اس کے بعد اس پارٹی میں بھی پھوٹ پڑی اور مولوی یونس خالص نے اپنا دھڑا علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد عبد الرب سیاف سعودی عرب سے آئے، ان تینوں تنظیموں کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد بنایا اور پھر اسی اتحاد کی بنا پر ’’اتحادِ اسلامی‘‘ کے نام سے اپنی پارٹی بنا ڈالی۔ اس کے بعد روایت پسندوں نے پہلے صبغۃ اللہ مجددی کی قیادت میں ’’دی افغانستان نیشنل لبریشن فرنٹ‘‘ بنائی اور محمد نبی محمدی نے ’’حرکتِ انقلابِ اسلامی‘‘ بنائی۔ اس کے بعد شاہ پرستوں نے پیر گیلانی کی قیادت میں ’’محاذِ ملی اسلامی‘‘ کے نام سے تنظیم قائم کی۔
اس مختصر تاریخ سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اصل پارٹی ایک تھی اور پھر یہی پارٹی انڈے بچے دیتی رہی اور ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی رہی۔ یہ تقسیم صرف اندرونی عوامل کا نتیجہ تھی یا اس میں بیرونی قوتوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ان کے علاوہ اہلِ تشیع کی بھی دو تنظیمیں (واضح رہے کہ ایک نہیں، بلکہ دو) وجود میں آ گئیں۔ تمام تنظیموں کو پاکستان کے توسط سے بیرونی امداد ملتی رہی۔ اور ان میں سے ہر تنظیم نے افغانستان کے اندر مختلف علاقوں پر اپنا اثر قائم کر لیا۔ حتٰی کہ فروری ۱۹۸۹ء میں دس حکومتیں بیک وقت قائم ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک تنظیم کے پاس مالی وسائل بھی ہوں، اسلحہ بھی ہو اور ایک علاقہ بھی ہو تو وہ اپنی ریاست قائم کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ چنانچہ سات سنی اور دو شیعہ تنظیموں کے اپنے اپنے زیرِ اثر علاقے تھے، اور کابل پر پہلے نجیب اللہ اور پھر دوستم کی علیحدہ حکومت تھی۔ ان آٹھ برسوں میں مسلسل خانہ جنگی رہی، اس لیے یہ وقت افغانیوں پر بہت بھاری گزرا۔
اس خانہ جنگی کے ردِعمل کے طور پر اکتوبر ۱۹۹۴ء میں ’’طالبان تحریک‘‘ شروع ہوئی۔ پاکستان نے بھی اپنا پورا زور اس کی حمایت میں ڈال دیا۔ اگلے دو برسوں میں طالبان نے بیشتر علاقے فتح کر لیے۔ ستمبر ۱۹۹۶ء میں کابل بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے ڈیڑھ سال میں انہوں نے بیشتر شمالی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ فی الوقت طالبان ۹۰ فیصد علاقے پر قابض ہیں۔ پچھلے پانچ برس سے ان کی جنگ شمالی اتحاد کے احمد شاہ مسعود سے جاری ہے، جس کا کوئی نتیجہ فی الحال برآمد نہیں ہو رہا۔
درج بالا مختصر تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف وہی جنگِ آزادی حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکتی ہے جو ایک ہی تنظیم اور ایک ہی قائد کے تحت ہو۔ یہ لازم تھا کہ جمعیتِ اسلامی نہ ٹوٹتی، یا اس کو نہ توڑا جاتا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ ۱۹۷۹ء ہی سے افغانستان کی ایک متفقہ جلاوطن حکومت قائم کر دی جاتی۔ یہی حکومت جہاد کو کنٹرول کرتی اور اسی حکومت کو بیرونی امداد ملتی۔ اگر ایسا ہوتا تو روسی افواج کے نکلتے ہی ۱۹۸۹ء میں پراَمن انتقالِ اقتدار ہو جاتا اور افغان عوام کو شدید ترین مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔
طالبان تحریک کی کامیابی میں جن عوامل نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، ان میں حکومتِ پاکستان کی طرف سے باقی تمام تنظیموں کی حمایت سے دست کشی اور طالبان تحریک کی مکمل حمایت، طالبان کا ایک ہی قائد کے جھنڈے تلے کامل اتحاد، اور افغان عوام کی طویل خانہ جنگی سے بے زاری شامل ہیں۔
معز امجد اور ڈاکٹر محمد فاروق کے جواب میں
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
محترم جاوید احمد غامدی کے بعض ارشادات کے حوالے سے جو گفتگو کچھ عرصے سے چل رہی ہے اس کے ضمن میں ان کے دو شاگردوں جناب معز امجد اور ڈاکٹر محمد فاروق خان نے ماہنامہ اشراق لاہور کے مئی ۲۰۰۱ء کے شمارے میں کچھ مزید خیالات کا اظہار کیا ہے جن کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
معز امجد صاحب نے حسب سابق (۱) کسی مسلم ریاست پر کافروں کے تسلط کے خلاف علماء کے اعلان جہاد کے استحقاق (۲) زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور ٹیکس کی ممانعت (۳) اور علماء کے فتویٰ کے آزادانہ حق کے بارے میں اپنے موقف کی مزید وضاحت کی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر محمد فاروق خان نے (۱) شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے فتوائے جہاد (۲) الجزائر کی جنگ آزادی (۳) اور جہاد افغانستان کے تاریخی تناظر کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ اور اسی ترتیب سے ہم ان کے خیالات و ارشادات پر تبصرہ کریں گے۔
جناب غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاد کے اعلان کا حق اسلامی ریاست کے سوا کسی کو نہیں ہے جس کے جواب میں ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی مسلم علاقہ پر کافروں کا تسلط قائم ہو جائے اور اسلامی ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے تو علماء کرام اور دینی قیادت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کافرانہ تسلط کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے مزاحمت کریں اور اسلامی اقتدار بحال کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ یمن پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسود عنسی نے قبضہ کر لیا تھا اور حضرت فیروز دیلمیؒ اور ان کے رفقاء نے گوریلا طرز پر شب خون مار کر اسود عنسی کو قتل کر دیا تھا جس سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کا اقتدار بحال ہوگیا۔ اس لیے اب بھی ایسی صورت میں کافروں کے تسلط کا شکار ہونے والے مسلمانوں کے لیے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس تسلط کو قبول نہ کریں، اس کے خاتمہ کے لیے جو ان کے بس میں ہو کر گزریں اور اس سلسلے میں ان کی جدوجہد کو شرعی جہاد کا درجہ حاصل ہوگا۔
معز امجد صاحب نے ہمارے استدلال کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ’’یہ واقعہ اس طرح رونما ہوا ہی نہیں جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا ہے‘‘۔ لیکن خود انہوں نے واقعہ کی جو تفصیلات بیان کی ہیں ان میں اس بات کو من و عن تسلیم کیا گیا ہے کہ اسود عنسی کو حضرت فیروز دیلمیؒ اور ان کے رفقاء نے قتل کیا تھا جس سے اس کی حکومت ختم ہو کر مسلمانوں کا اقتدار بحال ہوگئی تھا البتہ اتنے واقعہ کو بعینہ تسلیم کرتے ہوئے معز امجد صاحب نے اس میں دو اضافے فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت فیروز دیلمیؒ اور ان کے رفقاء کو اس کارروائی کا حکم خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اس مسئلہ پر یمن کے مسلمانوں کا اجتماع ہوا جس میں اسود عنسی کے خلاف کاروائی کے لیے اجتماعی مشاورت ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تفصیل سے ہمارے بیان کردہ واقعہ کی تردید کس طرح ہوگئی جسے موصوف اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ واقعہ اس طرح رونما ہوا ہی نہیں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ واقعہ تو وہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ کارروائی حضرت فیروز دیلمیؒ اور ان کے رفقاء نے از خود نہیں کی تھی بلکہ جناب نبی اکرمؐ کی ہدایت اور دوسرے مسلمانوں کے مشورہ سے کی تھی تو اس سے ہمارے موقف کی مزید تائید ہوتی ہے۔ مگر اس کی وضاحت سے قبل اس امر کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فیروز دیلمیؒ کے لیے جناب نبی اکرمؐ کی اس ہدایت کا ہمیں بھی علم تھا لیکن چونکہ وہ روایت جناب غامدی صاحب کے اصولوں کے مطابق ’’خبریت‘‘ کے قابل قبول معیار پر پوری نہیں اترتی تھی اس لیے ہم نے اس کا حوالہ نہیں دیا اور نفس واقعہ کا ذکر کر دیا۔ البتہ مسلمانوں کی مشاورت کا واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا تھا جس کا معز امجد صاحب نے ذکر کیا ہے، معلومات میں اس اضافے پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
ویسے استنباط و استدلال، تعبیر و تشریح اور اصول سازی کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کا یہ فائدہ تو ہوتا ہی ہے کہ جس بات پر جی چاہا اسے قبول کر لیا اور جسے ذہن نے قبول نہ کیا اس سے انکار کر دیا۔ جی نہ چاہا تو رجم کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایات قابل قبول قرار نہ پائیں اور کہیں ’’گیئر‘‘ پھنس گیا تو ’’اصابہ‘‘ کی روایت کا سہارا لینے میں بھی کوئی تامل نہ ہوا۔
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
واقعات کی ان تفصیلات کو تسلیم کرتے ہوئے جو جناب معز امجد صاحب نے بیان کی ہیں ہماری گزارش ہے کہ اس سے ہمارا یہ موقف مزید پختہ ہوگیا ہے کہ کسی مسلم علاقہ پر کافروں کے تسلط کی صورت میں وہاں کے مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس تسلط کے خاتمہ کے لیے جدوجہد کریں اور اس سلسلہ میں جناب نبی اکرمؐ کی ہدایت یہی ہے جو حافظ ابن حجرؒ کی اصابہ کے حوالہ سے معز امجد صاحب نے نقل کی ہے کہ جناب نبی اکرمؐ نے حضرت فیروز دیلمیؒ اور ان کے رفقاء کو اسود عنسی کے خلاف کاروائی کا حکم دیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ معز امجد صاحب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بحیثیت حاکم دیا تھا اور ہمارے نزدیک اس میں ان کی پیغمبرانہ حیثیت بھی شامل ہے۔ اس لیے اب بھی اگر دنیا کے کسی حصے میں کسی مسلم علاقہ پر کافروں کا تسلط ہو جائے تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے جناب نبی اکرمؐ کی ہدایت اور حکم وہی ہے جو یمن کو اسود عنسی کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے حضرت فیروز دیلمیؒ اور ان کے رفقاء کو دیا گیا تھا۔
پھر یہ نکتہ بھی یہاں قابل غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صوبہ میں بغاوت کو کچلنے کے لیے صرف ریاستی کاروائی کرنا ہوتی تو اس کے لیے فوج کشی مدینہ منورہ سے ہوتی مگر نبی اکرمؐ ریاست کی طرف سے یہ فوج کشی کرنے کی بجائے یمن کی مقامی آبادی کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اسود عنسی کے تسلط کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ ’’اصابہ‘‘ کی جس روایت کا معز امجد صاحب نے حوالہ دیا ہے اس کے مطابق نبی اکرمؐ نے حضرت فیروز دیلیؒ اور ان کے رفقاء کو اسود عنسیؒ کے خلاف ’’محاربہ‘‘ کا حکم دیا ہے۔ اب محاربہ کے معنی و مفہوم کے بارے میں اور کسی کو تردد ہو تو ہو مگر غامدی صاحب کے شاگردوں سے یہ توقع نہیں کی ہو سکتی کہ وہ اس کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ معز امجد صاحب اس واقعہ کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و ہدایت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس واقعہ کو جہاد کی حیثیت دینے میں تامل انہیں ہے جیسا کہ ان کا ارشاد گرامی ہے کہ:
’’یہ جابر و غاصب قوم کے خلاف گروہ بندی اور جتھابندی کر کے جہاد کرنے کا واقعہ نہیں بلکہ ایک غاصب حکمران کے قتل کا واقعہ ہے۔ گروہ بندی اور جتھا بندی کر کے جہاد کرنا اور کسی (اچھے یا برے) حکمران کے قتل کی سازش کرنا دو بالکل الگ معاملات ہیں۔‘‘
واقعہ کی ان تفصیلات کو ایک بار پھر ترتیب وار دیکھ لیں جو خود معز امجد صاحب نے بیان کی ہیں کہ یمن میں اسود عنسی کے تسلط کے بعد جناب نبی اکرمؐ نے یمن کے لوگوں کو اس کے خلاف محاربہ کا حکم دیا۔ اس حکم کے بعد یمن کے مسلمانوں کا مشاورتی اجتماع ہوا جس میں اسود عنسی کے خلاف کارروائی کے فریقوں کا جائزہ لیا گیا، اس کے بعد حضرت فیروز دیلمیؓ، حضرت قیس بن مکثوحؓ اور حضرت دادویہؓ نے گروپ بنایا اور اسود عنسی کے حرم میں زبردست شامل کی جانے والی خاتون آزادؓ کے ساتھ ساز باز کر کے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ اور پھر معز امجد صاحب کے حوصلہ کی داد دیجئے کہ اس سب کچھ کے باوجود ان کے نزدیک اس کاروائی کو شرعی جہاد کی حیثیت حاصل نہیں ہے اور وہ اسے ’’محض ایک غاصب حکمران کے قتل کی سازش‘‘ ہی تصور کر رہے ہیں۔ اور مزید لطف کی بات یہ ہے کہ واقعہ کی یہ ساری تفصیلات خود بیان کرنے کے بعد معز امجد صاحب اس سے نتیجہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ:
’’اس ساری کارروائی کا عملی ظہور اسود عنسی کے اپنے گروہ میں پھوٹ پڑنے اور اس کے اپنے ہی عمال کی طرف سے اس کے قتل کو کامیاب بنانے کی صورت میں ہوا۔‘‘
اس ’’ذہنی گورکھ دھندے‘‘ پر اس کے سوا کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ:
نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں
زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس کا جواز
جاوید احمد غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام میں زکوٰۃ کے سوا اور کوئی ٹیکس لگانے کا جواز نہیں ہے۔ ہم نے اس پر عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور ٹیکس کی شرعی ممانعت پر کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ اس پر معز امجد صاحب اور خورشید ندیم صاحب نے قرآن کریم اور سنت نبویؐ سے اپنے موقف کے حق میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں اور اپنے استدلال و استنباط کو مستحکم کرنے کے لیے خاصی تگ و دو کی ہے جس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔ ان دلائل سے ان کا موقف ثابت ہوا یا نہیں مگر اتنی بات ضرور واضح ہوگئی ہے کہ قرآن و سنت کی راہنمائی کے حوالے سے یہ مسئلہ صراحت او رقطعیت کے دائرہ کا نہیں بلکہ استدلال اور استنباط کی سطح کا ہے۔ ورنہ انہیں اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں بات استدلال و استنباط کی ہوگی وہاں سب اہل علم کے لیے گنجائش ہوگی کہ وہ استدلال و استنباط کا حق استعمال کریں۔ اور کسی شخص یا گروہ کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے استدلال و استنباط کے نتیجے کو حتمی اور قطعی قرار دے کر دوسرے کی سرے سے نفی کر دے۔
اس سلسلہ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے معز امجد صاحب کی ایک ذہنی الجھن کو دور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ فقہاء اسلام نے ’’نوائب‘‘ اور ’’ضرائب‘‘ کے عنوان سے ان ٹیکسوں کے احکام بیان فرمائے ہیں جو ایک اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان رعیت پر عائد کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے معز امجد صاحب نے لکھا ہے:
’’ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد کسی شخص کی بات یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ اسے ان آیات و ارشادات سے نکلنے والے حکم پر ترجیح دی جائے۔‘‘
اسی طرح وہ یہ فرماتے ہیں کہ:
’’لوگوں کی آرا کا حوالہ دینے کی بجائے ہمارے استدلال کی غلطی واضح کریں۔‘‘
اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ فقہاء اسلام کی آرا کو قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ترجیح دینے کا تاثر سراسر مغالطہ نوازی ہے کیونکہ یہ ترجیح آیات و ارشادات پر نہیں بلکہ ان سے بعض لوگوں کے استدلال پر ہے۔ اب ایک طرف انہی آیات و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن الہمامؒ اور دوسرے فقہاء کرام ’’نوائب و ضرائب‘‘ کے عنوان سے اسلامی حکومت کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ضرورت کے وقت ٹیکس لگانے کی اجازت دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان آیات و احادیث سے جناب جاوید احمد غامدی ان ٹیکسوں کے عدم جواز کا استدلال کر رہے ہیں۔ اس بحث میں اگر میرے جیسا کوئی طالب علم یہ کہہ دے کہ علامہ ابن الہمامؒ اور دوسرے فقہاء کا استدلال غامدی صاحب کے استدلال پر فائق ہے تو اسے کسی شخص کی بات کو قرآن و سنت کے ارشاد پر ترجیح دینے سے تعبیر کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اور جناب غامدی کے استدلال و استنباط کو قرآن و سنت کے ارشادات اور ان سے نکلے ہوئے احکام کا درجہ کب سے حاصل ہوگیا ہے؟ پھر ’’لوگوں کی آرا‘‘ کی پھبتی بھی خوب رہی۔ حالانکہ ہم نے ’’لوگوں کی آرا‘‘ کا حوالہ نہیں دیا بلکہ فقہاء اسلام کے فیصلوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ فقہاء اسلام جن کے فقہ و اجتہاد پر امت کے بڑے حصے کو اعتماد ہے اور جن کے فتاویٰ کی بنیاد پر صدیوں تک اسلامی عدالتوں میں فیصلے صادر ہوتے رہے ہیں۔
ہمارے ایک بزرگ تھے جن کا انتقال ہوگیا ہے، انہیں اپنے بعض تفردات کے حوالے سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا یہ ارشاد دہرانے کا بڑا شوق تھا اور وہ عام جلسوں میں بڑے ترنم کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ’’ھم رجال و نحن رجال‘‘ (وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں)۔ اس سے ان کا مطلب و مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی مسئلہ میں امت کے اکابر اہل علم سے انہیں اختلاف ہے تو وہ اس کا حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں۔ ایک مجلس میں اس کا تذکرہ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے قول کا بہت غلط استعمال ہے اور امام صاحبؒ پر ظلم ہے کیونکہ امام صاحبؒ کا اس قول سے ہرگز یہ مطلب نہیں تھا جو یہ بزرگ بیان کر رہے ہیں۔ امام صاحبؒ کا پورا ارشاد اس طرح ہے کہ:
’’اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سامنے آجائے تو سر آنکھوں پر۔ اگر وہ نہ ہو اور صحابہ کرامؓ کا کوئی اجماعی فیصلہ مل جائے تو ہم اس سے انحراف نہیں کرتے۔ اور اگر صحابہ کرامؓ کے اقوال کسی مسئلہ میں مختلف ہوں تو ہم انہی میں سے کوئی قول لے لیتے ہیں اور صحابہ کرامؓ کے اقوال کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ البتہ ان کے بعد کے کسی بزرگ کی رائے ہو تو ’’ھم رجال ونحن رجال‘‘ وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں‘‘۔
امام ابوحنیفہؒ چونکہ تابعی تھے اور باقی تابعین ان کے معاصرین کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے یہ بات انہوں نے اپنے معاصرین کے بارے میں فرمائی ہے کہ جس طرح انہیں استدلال و استنباط کا حق ہے اسی طرح ہمیں بھی اس کا حق حاصل ہے اور ہمارے درمیان دلائل کے علاوہ اور کسی بات کو ترجیح نہیں ہوگی۔ جبکہ اپنے متقدمین کے بارے میں وہ یہ حق تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی بات صرف اس حوالے سے بھی قابل ترجیح ہے کہ وہ صحابہ کرامؓ یا کسی صحابیؓ کی رائے ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کوئی شخص ’’ھم رجال ونحن رجال‘‘ کا نعرہ اپنے معاصرین کے حوالے سے لگاتا ہے تو ہم اس کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں مگر اس نعرہ کی آڑ میں کسی کو ائمہ کرامؒ، فقہاء عظامؒ او رمحدثین کرامؒ کی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اس کے بعد استدلال کے حوالے سے بھی ایک بار پر غور کر لیا جائے تو مناسب ہوگا۔ معز امجد صاحب نے مسلم شریف کی روایت پیش کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:
’’مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہٰ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وہ یہ شرائط پوری کر دیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس سے محروم کر دیے جائیں۔ رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔‘‘
ہم نے اس سلسلہ میں عرض کیا تھا کہ ’’الا بحقھا‘‘ کی جو استثنا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی مال میں ایسا حق باقی ہے جو ’’عصموا‘‘ کی ضمانت میں شامل نہیں ہے۔ اس پر معز امجد صاحب کو دو اشکال ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس استثنا کو مان لیا جائے تو جناب نبی اکرمؐ نے جس امان کی ضمانت دی ہے وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ استثنا صرف زکوٰۃ سے نہیں بلکہ جان کے حوالے سے بھی ہے۔ ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ ’’الا بحقھا‘‘ کی استثنا جان اور مال دونوں کے حوالے سے ہے اور دونوں صورتوں میں یہ استثنا موجود ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے، نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کے باوجود اگر کسی مسلمان کی جان و مال سے کسی حق کے عوض تعرض ضروری ہوا تو ’’عصموا منی‘‘ کی ضمانت کے تحت اسے تحفظ حاصل نہیں ہوگا اور اس کی جان و مال سے تعرض روا ہوگا۔ مثلاً جان کے حوالے سے یہ کہ کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کا قتل جائز ہوگا۔ کوئی شادی شدہ مسلمان زنا کا مرتکب ہے تو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق اسے سنگسار کیا جائے گا ۔ اور اگر کوئی مسلمان (نعوذ باللہ) مرتد ہوگیا ہے تو اسے بھی شرعی قانون کے مطابق توبہ نہ کرنے کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے مال میں ریاست یا سوسائٹی کا کوئی حق متعلق ہوگیا ہے تو اس سے ضرورت کے مطابق مال لیا جا سکے گا۔
سوال یہ ہے کہ اگر جان کی ضمانت سے استثنا کی صورتیں موجود ہیں تو مال کی حفاظت کی ضمانت سے استثنا کا امکان کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ اور اگر کسی بھی درجہ کی شرعی دلیل سے اس کی ضرورت اور جواز مل جاتا ہے تو اسے ’’عصموا منی‘‘ کی ضمانت کے منافی قرار دینے کا آخر کیا جواز ہے؟ اس لیے ان دونوں صورتوں میں تمام تر موجود اور ممکنہ استثناؤں کے باوجود ’’عصموا منی‘‘ کی ضمانت بدستور موجود و قائم ہے اور اسے (نعوذ باللہ) بے معنی سمجھنا محض خام خالی ہے۔
اگر معز امجد صاحب کو یاد ہو تو ہمارا پہلا اور اصولی سوال یہ تھا کہ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور ٹیکس کی ممانعت کی کوئی صریح دلیل موجود ہے تو ہماری راہنمائی کی جائے مگر ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی واضح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے اور وہ بھی اپنا موقف استدلال و استنباط کے ذریعے ہی واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس تکلف میں پڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ امت کے اجماعی تعامل اور فقہاء امت کے استدلالات کو محض اس شوق پر دریا برد کر دیں کہ ہمارے ایک محترم دوست جاوید احمد غامدی صاحب نے نئے سرے سے قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح اور اجتہاد و استنباط کا پرچم بلند کر دیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی معز امجد صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے نزدیک ان کے استدلال کی دیگر کئی باتوں کے علاوہ ایک اصولی اور بنیادی غلطی یہ بھی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح اور اجتہاد و استنباط میں امت کے اجماعی تعامل اور جمہور اہل علم کے موقف کو بہت سے معاملات میں نظر انداز کر رہے ہیں جس کی ہمارے ہاں کسی درجہ میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اگر جمہور اہل علم اور امت کے اجماعی تعامل کو کراس کر کے قرآن و سنت سے براہ راست استنباط و استدلال کا دروازہ کھول دیا جائے تو موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں امت مسلمہ میں ہزاروں مکاتب فکر وجود میں آئیں گے جو فکر و استدلال کے محاذ پر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں گے اور وہ دھماچوکڑی مچے گی کہ الامان والحفیظ۔
کچھ عرصہ قبل محترم ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال صاحب نے یہ مہم شروع کر دی تھی کہ قرآن و سنت کی ازسرنو تعبیر و تشریح کی جائے اور اجتہاد و استنباط کا حق علماء کی بجائے پارلیمنٹ کو دیا جائے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی تھی کہ امت میں اس وقت جو فرقہ بندی ہے اس سے نجات کی صورت اس کے سوا ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ایک مضمون میں ان سے گزارش کی تھی کہ ان کا یہ فارمولا تو ’’بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہوگیا‘‘ کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ اس وقت امت کا بڑا حصہ اعتقادی طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہے: اہل سنت اور اہل تشیع۔ جبکہ اہل سنت فقہی طور پر پانچ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور ظاہری۔ یہ سب مل کر زیادہ سے زیادہ آٹھ دس گروہ بنتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں عالمگیریت کا عنصر موجود ہے۔ جبکہ انہیں ختم کر کے مسلم ممالک کی اسمبلیوں کے ذریعے اجتہاد و استنباط کا دروازہ کھولا جائے گا تو دیگر کئی قباحتوں کے علاوہ ایک بڑی قباحت یہ ہوگی کہ مسلم ممالک اور ان کی قومی و صوبائی اسمبلیوں کی تعداد کے حساب سے سینکڑوں نئے فقہی مذاہب وجود میں آجائیں گے جو سب کے سب علاقائی ہوں گے اور ملت اسلامیہ کی رہی سہی وحدت بھی پارہ پارہ ہو کر رہ جائے گی۔
فتویٰ اور قضا
جناب جاوید غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتویٰ کے نظام کو ریاستی نظام کے تابع ہونا چاہیے اور علماء کو آزادانہ فتویٰ کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ فتویٰ کا معنی ہی کسی عالم دین کی آزادانہ رائے ہے، اسے اگر آزادی سے محروم کر دیا جائے تو وہ سرے سے فتویٰ ہی نہیں رہتا بلکہ قضا یا حکم کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں معز امجد صاحب نے اپنے حالیہ مضمون میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں صرف اس فتویٰ پر اعتراض ہے جس میں فتویٰ کو قضا کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں اس سلسلہ میں بحث کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی وضاحت ضروری ہے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم ہو اور شرعی قوانین کی عملداری کا نظام موجود ہو وہاں قضا کا متوازی نظام قطعی طور پر غلط اور خروج کے حکم میں ہوگا، لیکن جہاں مسلمانوں پر کافروں کا اقتدار ہو وہاں مسلمانوں کو قابل عمل حدود میں قضا کا داخلی نظام قائم کرنے کا حق حاصل ہے جیسا کہ اندلس کے شہر قرطبہ پر کفار کے تسلط کے بعد علامہ ابن الہمامؒ نے فتویٰ دیا تھا کہ:
’’قرطبہ جیسے شہر جہاں کافر والی بن جائیں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے میں سے کسی پر متفق ہو کر اسے والی بنائیں جو ان کے لیے قاضی متعین کرے یا خود فیصلے کرے۔‘‘ (فتح القدیر)
اس طرح کا فتویٰ ’’فتاویٰ عالمگیریہ‘‘ میں بھی موجود ہے اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ نے جب ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ جمعہ و عیدین اور دیگر شرعی احکام کی بجا آوری کے لیے اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کریں۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا فتویٰ
ہم نے عرض کیا تھا کہ دمشق پر تاتاریوں کی یلغار کے موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا جو کسی ریاستی نظام کے تحت نہیں بلکہ آزادانہ حیثیت سے تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ اگر حالات ایسی صورت اختیار کر لیں تو علماء کو حق حاصل ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں اور امت کی عملی قیادت کریں۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب نے اس واقعہ کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ ابن تیمیہؒ نے یہ فتویٰ دے کر ریاستی نظام کو سہارا دیا تھا۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ اور نہ ہی اس سے ہمارے موقف میں کوئی فرق ہی پڑتا ہے۔ اصل بات اپنی جگہ قائم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے یہ فتویٰ کسی ریاستی نظم کے تحت دیا تھا یا آزادانہ حیثیت سے اپنی دینی و علمی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا؟ اس بات کی کوئی وضاحت ڈاکٹر صاحب نہیں کر سکے۔
الجزائر کی جنگ آزادی
ڈاکٹر محمد فاروق خان نے الجزائر کی جنگ آزادی کی تاریخ یوں بیان کی ہے کہ ۱۹۵۴ء میں محاذ حریت وطنی قائم ہوا۔ ۱۹۵۸ء میں قاہرہ میں فرحت عباس کی سربراہ میں الجزائر کی جلاوطن حکومت قائم ہوئی اور ۱۹۶۲ء میں الجزائر آزاد ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ۱۹۴۰ء میں پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی اور ۱۹۴۷ء میں پاکستان وجود میں آگیا اور اس کی پشت پر علماء کے مسلسل جہاد آزادی، بالاکوٹ اور شاملی کے معرکوں، قبائلی عوام کی جنگ، حاجی شریعت اللہؒ، سردار احمد خان کھرلؒ، حاجی صاحب ترنگ زئیؒ اور تیتومیرؒ کے معرکہ ہائے حریت اور لاکھوں علماء کرام اور عوام کی جانوں کی قربانیوں کو یوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے ان واقعات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الجزائر کی جنگ آزادی ۱۹۵۴ء میں شروع ہو کر صرف آٹھ سال میں منزل تک نہیں پہنچ گئی تھی بلکہ اس کے پیچھے لاکھوں مجاہدین آزای کا خون ہے اور ان میں وہ غریب مولوی بھی شامل ہیں جن کا نام لیتے ہوئے محترم غامدی صاحب کے شاگردوں کو نہ جانے کیوں حجاب محسوس ہوتا ہے۔ الشیخ عبد الحمید بن بادیسؒ اور الشیخ ابراہیمیؒ تو جہاد آزادی کے صف اول کے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جہاد کا فتویٰ دے کر اور جمعیۃ العلماء الجزائر قائم کر کے جہاد میں حصہ لیا تھا۔ انہی علماء کی وجہ سے لاہور میں الجزائر کے جہاد آزادی کی حمایت میں حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کی قیادت میں رائے عامہ کو بیدار کرنے کی مہم چلائی گئی تھی۔ الجزائر کی آزادی کے بعد الشیخ ابراہیمیؒ لاہور تشریف لائے تھے جن کا شاندار استقبال کیا گیا تھا اور الشیخ بن بادیسؒ کی انہی خدمات کے اعتراف میں لاہور میونسپل کارپوریشن نے ایک سڑک کو بن بادیس روڈ کے نام سے موسوم کیا تھا۔
جہاد افغانستان
ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب نے جہاد افغانستان کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے مگر کیا مجال کہ کسی غریب مولوی کا نام ان کی نوک قلم پر آنے پائے سوائے مولوی محمد یونس خالص کے کہ ان کا تذکرہ انجینئر گلبدین حکمت یار کی جماعت میں تفریق بیان کرنے کے لیے ضروری ہوگیا تھا۔ حالانکہ مولوی محمد نبی محمدی، مولوی جلال الدین حقانی، مولوی نصر اللہ منصور اور مولوی ارسلان رحمانی جہاد آزادی کے عملی قائدین میں سے ہیں ۔جبکہ مولوی جلال الدین حقانی نے خوست چھاؤنی کی فتح میں اور مولوی ارسلان رحمانی نے ارگون چھاؤنی کی فتح میں مجاہدین کی خود کمان کی تھی۔ لیکن چونکہ مولویوں کے تذکرے سے جہاد کی شرعی حیثیت کا تاثر ابھرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اسے صرف جنگ آزادی کی حد تک دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے مولویوں کا تذکرہ ہی سرے سے غائب کر دیا ہے۔
خاتمہ کلام
ہمارا خیال ہے کہ اس بحث کو یہیں سمیٹ لیا جائے، اسی لیے اب تک دونوں طرف سے شائع ہونے والے کم و بیش سبھی مضامین یکجا شائع کیے جا رہے ہیں تاکہ اہل علم کو مطالعہ اور تجزیہ میں آسانی رہے۔ دونوں طرف کے دلائل سامنے آچکے ہیں، مزید تکرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں محترم جاوید احمد غامدی اور ان کے شاگردان گرامی کی خدمت میں برادرانہ طور پر چند معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں:
- ہمیں ان کے مطالعہ و تحقیق اور استنباط و استدلال کے حق سے کوئی انکار اور اختلاف نہیں ہے مگر اس بات سے ضرور اختلاف ہے کہ وہ اپنے استدلال و استنباط کو صرف اس لیے حرف آخر قرار دے رہے ہیں کہ ان کی سوئی اس نکتہ سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ ان کی جو بات جمہور اہل علم کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی ہمیں بھی اسے تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بات جمہور اہل علم کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی تو بھی اسے قبول نہ کرنے کے باوجود دیگر اصحاب علم کے تفردات کی طرح ہم ان کا احترام کریں گے۔
- اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک سنت رسولؐ کے ساتھ ساتھ جماعت صحابہؓ قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کا معیار ہے، اسی طرح امت کا اجماعی تعامل بھی قرآن و سنت کی منشا و مصداق تک پہنچنے کا محفوظ راستہ ہے اور ان دائروں کو کراس کرنے کا مطلب اہل سنت کی مسلمہ حدود کو کراس کرنا ہے۔ اس لیے الدین النصیحہ کے ارشاد نبویؐ کی رو سے میری برادرانہ درخواست ہے کہ استدلال و استنباط میں ان دائروں کا بہرحال لحاظ رکھا جائے کیونکہ خیر بہرحال اسی میں ہے۔
- مولوی غریب پر رحم کھایا جائے، گھر کے کامے فرد کی طرح سب سے زیادہ کام بھی اسی کے ذمہ ہیں، سب سے زیادہ بے اعتنائی کا شکار بھی وہی ہے اور سب سے زیادہ گالیاں بھی وہی کھاتا ہے۔ امت کو جب بھی قربانی کی ضرورت پڑی ہے مولوی نے آگے بڑھ کر مار کھائی ہے اور خون دیا ہے اور آج امت میں دینداری کی جو بھی رونق قائم ہے عالم اسباب میں اسی کے دم قدم سے ہے۔ آپ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو دین پڑھائیے یہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہے لیکن اس کے لیے غریب مولوی کو طنز و تعریض کے تیروں کا نشانہ بناتے رہنا ضروری تو نہیں۔
پاکستان شریعت کونسل کی مجلسِ شورٰی کے فیصلے
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
پاکستان شریعت کونسل کی مرکزی مجلسِ شورٰی نے صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ توڑنے اور نصابی کتب کی تدوین و اشاعت بین الاقوامی اداروں کے سپرد کرنے کے حکومتی فیصلے پر شدید نکتہ چینی کی ہے اور اسے ملک کے نصابِ تعلیم کو سیکولرائز کرنے کی مہم کا ایک حصہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مہم منظم کرنے کے لیے ملک کے دینی اور تعلیمی حلقوں سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ۲۹ اپریل ۲۰۰۱ء کو الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ میں منعقدہ پاکستان شریعت کونسل کی مرکزی مجلسِ شورٰی کے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت مرکزی امیر مولانا فداء الرحمٰن درخواستی نے کی اور اس سے مولانا زاہد الراشدی، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا قاری جمیل الرحمٰن اختر، پروفیسر ڈاکٹر احمد خان، پروفیسر حافظ منیر احمد، مولانا عبد العزیز محمدی، مولانا صلاح الدین فاروقی، مولانا حافظ مہر محمد میانوالوی، مولانا سخی داد خوستی، مولانا محمد نواز بلوچ اور دیگر راہنماؤں نے خطاب کیا۔
اجلاس میں ایک قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک کے تجارتی اور معاشی نظام کو بین الاقوامی اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تحویل میں دینے کے بعد اب تعلیمی نظام کو بھی بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سکول، کالج اور یونیورسٹی کے تعلیمی نصاب سے دینی مواد بالکل خارج ہو جائے گا اور اس کی جگہ سیکس اور میوزک کے مضامین نصاب کا حصہ بنیں گے، اور اس کے علاوہ نصابی کتابیں انتہائی مہنگی ہو جانے کے بعد غریب آدمی میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی بالکل سکت نہیں رہے گی، اس لیے یہ پروگرام ملک کے لیے تباہ کن ہے جس پر حکومت کو نظرِثانی کرنی چاہیے۔
پاکستان شریعت کونسل نے ایک اور قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق ملک میں سودی نظام کو ۳۰ جون تک ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں اور مزید تاخیری حربے اختیار کر کے قرآن کریم کے احکام کا مذاق نہ اڑایا جائے۔
مرکزی مجلس شورٰی کے اجلاس میں پاکستان شریعت کونسل کے نائب امیر مولانا منظور احمد چنیوٹی نے اپنے حالیہ دورۂ انڈونیشیا کی تفصیلات بیان کیں اور بتایا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے دیگر راہنماؤں علامہ ڈاکٹر خالد محمود، مولانا عبد الحفیظ مکی، مولانا طلحہ مکی، اور مولانا محمد الیاس چنیوٹی کے ہمراہ ۱۵ اپریل سے ۲۵ اپریل تک انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکرتا کا دورہ کیا جہاں مسیحی اور قادیانیوں کی مشنری سرگرمیاں اس وقت عروج پر ہیں اور حکومتی اداروں میں ان کا اثر و رسوخ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں انڈونیشیا کی دینی جماعتوں کے راہنماؤں سے تبادلۂ خیال کیا ہے اور ان کے مشورہ سے انڈونیشیا میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ قائم کر دی گئی ہے جس کا کنوینر شیخ محمد امین جمال دین کو مقرر کیا گیا ہے۔ م
مجلسِ شورٰی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان شریعت کونسل کے سربراہ مولانا فداء الرحمٰن درخواستی نے علماء اور دینی کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ دینی اقدار کے تحفظ اور مغرب کی ثقافتی یلغار کی روک تھام کے لیے سنجیدگی کے ساتھ محنت کریں۔
الشریعہ اکادمی کی انگلش لینگوئج کلاس اور فری ڈسپنسری کی افتتاحی تقریب
الشریعہ اکادمی، کنگنی والا، گوجرانوالہ میں علماء کرام اور دینی مدارس کے طلبہ کے لیے انگلش لینگوئج کورس اور الشریعہ فری ڈسپنسری کے آغاز کے موقع پر ۶ اپریل کو بعد نماز عصر ایک افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ جناب بابر یعقوب فتح محمد مہمان خصوصی تھے اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عیسٰی خان گورمانی دامت برکاتہم کی دعا اور نصائح سے کلاس اور ڈسپنسری کا افتتاح ہوا۔ تقریب سے مولانا زاہد الراشدی اور ممتاز آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر میجر (ر) عبد القیوم نے بھی خطاب کیا۔ جبکہ شرکاء میں شہر کے سرکردہ علماء کرام اور احباب کے علاوہ علامہ محمد احمد لدھیانوی، ڈاکٹر غلام محمد، جناب عثمان عمر ہاشمی، مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی، مولانا عبد القدوس قارن، مولانا عزیز الرحمٰن خان شاہد اور دیگر حضرات بھی شامل تھے۔
الشریعہ اکادمی کے ڈائریکٹر مولانا زاہد الراشدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام کے بارے میں یہ کہنا تاریخی طور پر غلط ہے کہ انہوں نے انگریزی زبان کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کے واضح ارشادات موجود ہیں جن میں انہوں نے انگریزی زبان کو بطور زبان سیکھنے کی حمایت کی ہے البتہ اکابر علماء کرام نے انگریزی کلچر کی مخالفت ضرور کی ہے اور اس کے ہم بھی مخالف ہیں۔
مولانا مفتی محمد عیسٰی خان گورمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزی زبان سیکھیں، اسی طرح افسران اور حکام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کی مہارت حاصل کریں تاکہ وہ قرآن کریم اور سنت نبویؐ سے استفادہ کر سکیں جو ہم سب کے لیے راہنمائی کا سرچشمہ ہے۔
ڈاکٹر میجر (ر) عبد القیوم نے کہا کہ انہیں الشریعہ اکادمی کے پروگرام سے بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ ان کے ایک پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید تعلیم سے علماء کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور وہ دین کی بہت زیادہ خدمت کر سکیں گے۔
الشریعہ اکادمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر حافظ محمد عمار خان ناصر نے شرکاء کو انگلش لینگوئج کورس کے پروگرام سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ کلاس دینی مدارس کے اساتذہ و طلبہ کے لیے ہو گی جو عصر سے مغرب تک ہوا کرے گی اور اس کے شرکاء سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کلاس کے لیے ۳۰ افراد نے داخلہ لیا ہے جن کو ان کی صلاحیت کے مطابق تین گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
مہمانِ خصوصی جناب بابر یعقوب فتح محمد ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے الشریعہ اکادمی کے پروگرام پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ اسلام کے بارے میں مغربی حلقوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زبان پر عبور حاصل کیا جائے اور ان کی بات کو پوری طرح سمجھ کر ان کی زبان میں دلیل و منطق کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بین الاقوامی زبانوں اور انفرمیشن کے جدید ذرائع سے استفادہ کیے بغیر اسلام کے پیغام کو دنیا تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’صوبہ سرحد کے علماء دیوبند کی سیاسی خدمات‘‘
پشاور میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ’’خدماتِ دارالعلوم دیوبند کانفرنس‘‘ کے موقع پر پشاور کے محترم اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الدیان کلیم نے ’’صوبہ سرحد کے علماء دیوبند کی سیاسی خدمات‘‘ کے نام سے ساڑھے تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل مجلد اور خوبصورت کتاب پیش کی ہے جو دراصل ان کے ڈاکٹریٹ کے مقالہ کا ایک حصہ ہے۔ مقالہ میں تحریکِ آزادی، تحریکِ پاکستان اور پھر پاکستان میں نفاذِ شریعت کی جدوجہد میں صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے علماء دیوبند کی خدمات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے اور بہت اہم معلومات یکجا کر دی گئی ہیں۔
کتاب کی قیمت ۱۵۰ روپے ہے اور مکتبہ شجاعت، راحت آباد، ڈاکخانہ فارسٹ کالج، پشاور سے طلب کی جا سکتی ہے۔
’’خلاصہ تفسیر القرآن متعلقہ الجہاد الاسلامی‘‘
مدرسہ قاسم العلوم شیرانوالہ گیٹ لاہور کے استاذ تفسیر حضرت مولانا حمید الرحمٰن عباسی مدظلہ مختلف عنوانات پر قرآن کریم کی آیات کریمہ، متعلقہ احادیث اور ضروری تشریحات الگ الگ مجموعوں کی صورت میں پیش کر رہے ہیں جو ایک قابل قدر کاوش ہے۔ زیرنظر دو جلدیں ۹ و ۱۰ جہاد کے بارے میں احکام و فضائل کے موضوع پر ہیں اور ان میں قرآن و حدیث کا اچھا خاصا ذخیرہ مرتب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
دونوں جلدوں کے مجموعی صفحات ایک ہزار سے زائد ہیں اور قیمت درج نہیں ہے۔
ملنے کا پتہ: دفتر انجمن خدام الدین، شیرانوالہ گیٹ، لاہور
’’ختم نبوت اور قادیانی‘‘
مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں نے اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے قرآن کریم کی آیت ختم نبوت کی درازکار تاویلات کا سہارا لے کر مکروفریب کا جو جال پھیلایا ہے، اسے ہر دور میں علماء حق نے دلائل کے ساتھ بے نقاب کیا ہے۔ زیرنظر کتابچہ اسی موضوع پر مولانا حکیم محمود احمد ظفر نے تحریر کیا ہے اور علمی انداز میں اہل اسلام کے موقف کی وضاحت کی ہے۔
صفحات ڈیڑھ سو سے زائد، قیمت درج نہیں۔ اور ملنے کا پتہ: ادارہ معارف اسلامیہ، مبارک پورہ، سیالکوٹ۔
’’عقیدۃ اہل الاسلام فی حیاۃ عیسٰی علیہ السلام‘‘
اس کتابچہ میں مولانا حکیم محمود احمد ظفر نے حضرت عیسٰی علیہ السلام کی حیاتِ جسمانی اور نزول کے بارے میں اہلِ اسلام کے اجماعی عقیدہ کی دلائل کے ساتھ وضاحت کی ہے اور قادیانی دلائل کے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا ہے۔ یہ کتابچہ ڈیڑھ سو صفحات پر مشتمل ہے اور مندرجہ بالا پتہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
’’ماہنامہ حق چاریارؓ کا مولانا محمد امین صفدرؒ نمبر‘‘
تحریکِ خدامِ اہلِ سنت کے ترجمان ماہنامہ ’’حق چاریارؓ‘‘ لاہور نے مناظرِ اہلِ سنت حضرت مولانا امین صفدرؒ کی علمی و دینی خدمات پر ساڑھے تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ضخیم اور معلوماتی نمبر پیش کیا ہے جس میں مولانا محمد امین صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیشتر خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔
قیمت ۱۲۰ روپے۔ ملنے کا پتہ: متصل جامع مسجد برکت علی، مدینہ بازار، ذیلدار روڈ، اچھرہ، لاہور۔
مسلمہ شخصیتوں کی آراء
مولانا محمد تقی امینی
فقہ اسلامی کا دسواں ماخذ مسلمہ شخصیتوں کی آراء ہیں۔ اس میں اقوال، فتاوٰی، ثالثی، عدالتی فیصلہ، سرکاری و غیر سرکاری ہدایتیں سب داخل ہیں، مگر مرکزی حیثیت صحابہ کرامؓ کی آراء کو حاصل ہو گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا:
’’میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کر لو گے، ہدایت مل جائے گی۔‘‘
صحابہؓ کی رایوں کے مستند ہونے پر دلائل
ان کے اکثر اقوال زبانِ رسالت سے سنے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے اجتہاد بھی کیا ہے تو ان کی رائے زیادہ صائب ہے کیونکہ انہوں نے نصوص کے موقع و محل کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے۔ دین میں انہیں تقدم حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فیضیاب ہوئے ہیں، ان کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے نزول اور اسرارِ شریعت کا مشاہدہ کیا ہے۔
(توضیح و تلویح فی تقلید الصحابی)
ان وجوہ کی بنا پر اگر وہ اپنی رائے سے بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ دوسروں کے مقابلہ میں بدرجہا فضیلت اور برتری کی مستحق ہوتی ہے۔
فقہاء نے صحابہؓ سے اخذ و استنباط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور قانونی امور میں ان کی خصوصیت کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب انسان یکساں نہیں ہوتے اس لیے سب صحابہؓ بھی یکساں نہیں تھے۔ اس لیے قانونی امور میں ان صحابہؓ کی رائے زیادہ وزنی ہو گی جن کی طرف اس عبارت میں اشارہ ہے:
’’جن صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی عمریں گزاری تھیں اور آپؐ کے پاکیزہ اخلاق کے رنگ میں رنگ گئے تھے، جیسے خلفاء راشدینؓ، ازواجِ مطہراتؓ، عبادلہ (عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، عبد اللہ بن عباسؓ)، حضرت انس ؓ، حضرت حذیفہؓ اور جو اُن کے طبقہ میں ہیں۔‘‘
(بحوالہ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر)
اگست ۲۰۰۱ء
امریکی نائب وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی نائب وزیرخارجہ محترمہ کرسٹینا روکا ان دنوں جنوبی ایشیا کے دورے پر ہیں اور جس وقت یہ سطور تحریر کی جا رہی ہیں وہ اسلام آباد میں پاکستانی حکام سے مذاکرات میں مصروف ہیں۔ جبکہ امارت اسلامی افغانستان کے سفیر محترم ملا عبد السلام ضعیف سے بھی ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد کرسٹینا روکا کا یہ پہلا دورۂ پاکستان ہے اور اخباری اطلاعات کے مطابق ان کے ایجنڈے میں (۱) پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی روک تھام (۲) افغانستان کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں پر مؤثر عمل درآمد (۳) عرب مجاہد اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا سوال (۴) اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے مسائل سرفہرست ہیں جن کے بارے میں وہ متعدد بیانات میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکی ہیں۔
جنوبی ایشیا کے حوالے سے امریکہ کا یہ ایجنڈا کوئی نیا نہیں ہے اور نہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی اور کلنٹن کی جگہ جارج ڈبلیو بش کی بطور صدر آمد سے اس ایجنڈے اور اس کے حوالے سے امریکہ کی قومی پالیسی میں کوئی فرق سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے ایجنڈے کی بنیاد اس کے اس زعم پر ہے کہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور واحد سپر پاور ہے اس لیے دنیا کے ہر خطے میں سیاست و معیشت اور قانون و عدالت سے لے کر اخلاق و معاشرت تک تمام شعبوں میں اس کی مرضی، خواہش اور پالیسی پر عمل ہونا چاہیے اور دنیا کے ہر ملک اور قوم کو صرف اور صرف امریکی مفادات کے تحفظ اور تکمیل کے حوالے سے اپنی پالیسیاں مرتب کرنی چاہئیں۔ امریکہ اپنی اس بالادستی کے لیے انسانی حقوق کے نعرے، جمہوریت کے پرچار اور اقوام متحدہ کے فیصلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے لیکن یہ محض فریب کاری ہے جس کا صرف دو عملی مثالوں سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے:
- ایک یہ کہ امریکہ پاکستان میں جمہوری عمل کی جلد بحالی کا خواہاں ہے اور پاکستان میں آنے والی نئی امریکی سفیر نے صاف طور پر کہا ہے کہ بطور سفیر ان کی پہلی ترجیح پاکستان میں جمہوری عمل کی بحالی ہوگی۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے ممالک میں امریکہ کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور چونکہ وہاں شخصی آمریتیں اور بادشاہتیں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو رہی ہے اس لیے امریکہ کے نزدیک ان ممالک کے عوام کی سیاسی آزادیوں، شہری حقوق اور جمہوری تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور امریکہ پورے مشرق وسطیٰ میں آمریتوں اور بادشاہتوں کا سب سے بڑا محافظ بنا ہوا ہے۔
- دوسری مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فیصلوں کی کھلے بندوں خلاف ورزی کرتا چلا آرہا ہے اور اب بھی اعلانیہ خلاف ورزی کر رہا ہے لیکن اسرائیل کو ان خلاف ورزیوں سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیموں کو مشرق وسطیٰ بھجوانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ جبکہ اس کے برعکس افغانستان کی سرحدوں پر صرف اس لیے اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیمیں بھجوانے کے لیے امریکہ سب سے زیادہ متحرک ہے کہ امریکہ کے اندازوں، توقعات اور خواہشات کے علی الرغم افغانستان کے عوام اقوام متحدہ کی اقتصادی پابندیوں کے باوجود اس طرح بھوکے نہیں مر رہے جس طرح امریکہ انہیں بھوکا مار کر اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا، اور وہاں نہ صرف طالبان کی حکومت کاروبار حکومت پورے اعتماد کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے بلکہ افغان عوام کو طالبان حکومت کے خلاف بھڑکانے اور بغاوت پر آمادہ کرنے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا۔
امریکی پالیسوں میں کھلے تضاد کی یہ دو واضح مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جمہوریت، انسانی حقوق، امن اور معاشرتی ترقی کے حوالے سے امریکہ کے نعرے اور دعوے کسی اصول اور فلسفہ کے فروغ کے لیے نہیں بلکہ محض اپنے مفادات کے حصول اور تحفظ کے لیے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس امر کی کہ امریکہ کو تمام تگ و دو کے باوجود دنیا پر اپنی پالیسیاں ہر حال میں مسلط کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور دنیا کے ہر خطے میں اس کی مخالفت اور اس کے خلاف نفرت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
ہم امریکی حکمرانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ جنوبی ایشیا کے ممالک پر اپنی یک طرفہ پالیسیاں طاقت کے زور پر مسلط کرنے کی پالیسی پر نظرثانی کریں اور دوسروں کے خلاف طاقت اور دباؤ کے اندھا دھند استعمال کے بجائے اپنی پالیسیوں کے تضادات اور طرزعمل کے دوغلے پن کا جائزہ لیں۔ محض طاقت کا استعمال نہ پہلے کبھی انسانی تاریخ کے کسی دور میں اپنے مطلوبہ اور مزعومہ مقاصد حاصل کر سکا ہے او رنہ اب کسی کو محض قوت اور طاقت کے سہارے اپنے مزعومہ مقاصد تک پہنچنے کی توقع کرنی چاہیے۔
حضرت عیسٰی علیہ السلام کی زیارت کے تین مبارک خواب
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
اللہ تعالیٰ نے راقم اثیم پر جو احسانات اور انعامات کیے ہیں، راقم اثیم قطعاً و یقیناً اپنے آپ کو ان کا اہل نہیں سمجھتا۔ یہ صرف اور صرف منعمِ حقیقی کا فضل و کرم ہے کہ حضراتِ علما اور طلبا اور خواص و عوام اس ناچیز سے محبت بھی کرتے ہیں اور قدردانی بھی کرتے ہیں۔ ڈھول اندر سے تو خالی ہوتا ہے مگر اس کی آواز دور دور تک جاتی ہے، یہی حال میرا ہے کہ علم و عمل، تقوٰی اور ورع سے اندر سے خالی ہے اور حقیقت اس کے سوا نہیں کہ من آنم کہ من دانم۔راقم اثیم تحریک ۱۹۵۳ء کی ختم نبوت کے دور میں پہلے گوجرانوالہ جیل میں، پھر نیو سنٹرل جیل ملتان میں کمرہ نمبر ۱۴ میں مقید رہا۔ ہماری بارک نمبر ۶ دو منزلہ تھی اور اس میں چار اضلاع کے قیدی تھے اور سب علما، تاجر اور پڑھے لکھے لوگ تھے جو دین دار تھے۔ اضلاع یہ ہیں: گوجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودھا اور کیمبل پور )فی الحال ضلع اٹک(۔ بحمد اللہ تعالیٰ جیل میں بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ راقم اثیم قرآنِ کریم کا ترجمہ، موطا امام مالک، شرح نخبۃ الفکر اور حجۃ اللہ البالغہ وغیرہ کتابیں پڑھاتا رہا۔ دیگر حضرات علماء کرام بھی اپنے اپنے ذوق کے اسباق پڑھتے پڑھاتے رہے۔ آخر میں راقم اثیم کمرہ میں اکیلا رہتا تھا کیونکہ باقی ساتھی رہا ہو چکے تھے اور میں قدرے بڑا مجرم تھا۔ تقریباً دس ماہ جیل میں رہا اور ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب برق کی تردید میں ’’صرف ایک اسلام بجواب دو اسلام‘‘ وہاں ملتان جیل ہی میں راقم اثیم نے لکھی تھی۔
خواب نمبر ۱
۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳ھ میں تقریباً سحری کا وقت تھا کہ خواب میں مجھ سے کسی نے کہا کہ حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں آ رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہاں تمہارے پاس تشریف لائیں گے۔ میں خوش بھی ہوا کہ حضرت کی ملاقات کا شرف حاصل ہو گا اور کچھ پریشانی بھی ہوئی کہ میں تو قیدی ہوں، حضرت کو بٹھاؤں گا کہاں اور کھلاؤں پلاؤں گا کیا؟ پھر خواب ہی میں یہ خیال آیا کہ راقم کے نیچے جو دری، نمدہ اور چادر ہے، یہ پاک ہیں، ان پر بٹھاؤں گا۔ خواب میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تشریف لائے۔ حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سر مبارک ننگا تھا، چہرہ اقدس سرخ، اور ڈاڑھی مبارک سیاہ تھی۔ لمبا سفید عربی طرز کا کرتا زیب تن تھا، اور نظر تو نہیں آتا تھا مگر محسوس یہ ہوتا تھا کہ نیچے حضرت نے جانگیہ اور نیکر پہنی ہوئی ہے۔ آپ کے خادم کا لباس سفید تھا، فٹ کرتا اور قدرے تنگ شلوار اور سر پر سفید اور اوپر کو ابھری ہوئی نوک دار ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔
راقم اثیم نے اپنے بستر پر، جو زمین پر بچھا ہوا تھا، دونوں بزرگوں کو بٹھایا۔ نہایت ہی عقیدت مندانہ طریقے سے علیک سلیک کے بعد راقم اثیم نے حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مودبانہ طور پر کہا کہ حضرت! میں ایک قیدی ہوں اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا، صرف قہوہ پلا سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، لاؤ۔ میں خواب ہی میں فورًا تنور پر پہنچا جہاں روٹیاں پکتی تھیں۔ اس تنور پر گھڑا رکھا اور اس میں پانی، چائے کی پتی اور کھانڈ ڈالی۔ تنور خوب گرم تھا، جلد ہی قہوہ تیار ہو گیا۔ راقم اثیم خوشی خوشی لے کر کمرہ میں پہنچا اور قہوہ دو پیالیوں میں ڈالا اور یوں محسوس ہوا کہ اس میں دودھ بھی پڑا ہوا ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ ان دونوں بزرگوں نے چائے پی، پھر جلدی سے حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور خادم بھی ساتھ اٹھ گیا۔ میں نے التجا کی کہ حضرت ذرا آرام کریں اور ٹھہریں، تو حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، ہمیں جلدی جانا ہے، پھر ان شاء اللہ العزیز جلدی آجائیں گے، یہ فرما کر رخصت ہو گئے۔
راقم اثیم اس خواب پر بہت خوش ہوا۔ فجر ہوئی اور ہمارے کمرے کھلے تو راقم اثیم استادِ محترم حضرت مولانا عبد القدیر صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو تحریکِ ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جیل میں مقید تھے، اور ان کے سامنے خواب بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا، میاں! تمہیں معلوم ہے کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں علیہم السلام کی شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تم نے واقعی حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا ہے اور میاں! ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی ہی میں تشریف لے آئیں۔
خواب نمبر ۲
راقم اثیم نے دوسری مرتبہ حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت شلوار پہنے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ذرا نیچے تک قمیص زیب تن تھی، اور سر مبارک پر سادہ سا کلّہ، اوپر پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور کوٹ میں، جو گھٹنوں سے نیچے تھا، ملبوس تھے اور بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ راقم اثیم کو پتہ چلا کہ حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام جا رہے ہیں تو راقم اثیم بھی پیچھے پیچھے چل پڑا اور سلام عرض کی۔ یوں محسوس ہوا کہ بہت آہستہ سے جواب دیا اور رفتار برقرار رکھی۔ راقم بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کافی دور جانے کے بعد زور زر کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت اس بارش میں بیٹھ گئے اور اوپر ایک سفید رنگ کی چادر تان لی۔ کافی دیر مغموم اور پریشان حالت میں بیٹھے رہے، پھر بارش میں ہی اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے اور پھر نظر نہ آئے۔
اس خواب کے چند دن بعد مہاجرینِ فلسطین کے دو کیمپوں صابرہ اور شتیلہ کا واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے تقریباً بتیس ہزار مظلوم مسلمان مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور مریضوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد راقم اثیم اس خواب کی تعبیر سمجھا کہ حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شدید بارش میں چادر اوڑھ کر بیٹھنا اور پریشان ہونا اس طرف اشارہ تھا کہ تقریباً ستر لاکھ ظالم یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہوا اور تقریباً تیرہ کروڑ کی آبادی پر مشتمل آس پاس کے مسلمان ممالک نے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اور مصلحت کی چادر اوڑھے رکھی۔
خواب نمبر ۳
بحمد اللہ تعالیٰ کارگل کی لڑائی سے چند دن پہلے تیسری مرتبہ حضرت عیسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ سفید لباس میں ملبوس تھے، اوپر واسکٹ تھا، سر مبارک ننگا تھا اور عینک لگائے ہوئے تھے۔ آپ کے اردگرد کچھ مستعد نوجوان تھے اور خاصی تعداد میں میلے اور ڈھیلے لباس والے طالبان قسم کی مخلوق تھی جو آپ کے حکم کی منتظر تھی، ملاقات ہوتے ہوئے آپ فورًا کہیں چلے گئے۔
سقوطِ حد کے بعد مجرم کو تعزیری سزا (۲)
قاضی محمد رویس خان ایوبی
قرائن پر اعتماد کرنے کے فقہی نظائر
(۱) غیر متزوجہ اور متوفی عنہا زوجہا اور مطلقہ کو بعد از انقضاءِ عدت حمل ظاہر ہو جائے تو یہ بدکاری کا قرینہ ہو گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ حمل حرام اکراہ سے ہوا ہو یا رضا سے، لیکن حمل قرینہ زنا ضرور ہے۔ سو اگر عورت اقرار نہ بھی کرے اور اکراہ کا ثبوت بھی پیش نہ کرے تو حد تو ساقط ہو جائے گی مگر اسے تعزیری سزا ضرور دی جائے گی۔
(۲) یہی صورتحال قسامہ میں ہے۔ اگر کسی بستی میں کسی مقتول کی لاش ملے مگر قاتل کا پتہ نہ چل سکے تو اہلِ محلہ کے پچاس بالغ مردوں سے قسم لی جائے گی کہ نہ انہیں قاتل کا علم ہے اور نہ ان میں سے کوئی قاتل ہی ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیں تو انہیں مقتول کی دیت ادا کرنا ہو گی۔ یعنی قسموں سے انکار اس امر کا قرینہ ہے کہ قاتل اہلِ محلہ میں سے ہی کوئی ہے۔
(۳) شرابی کے منہ سے شراب کی بو بھی شراب نوشی کا قرینہ سمجھا گیا ہے اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے ارتکابِ جرم کیا ہے۔
(۴) مالِ مسروقہ کا چور کے گھر سے برآمد ہونا اس کے ارتکابِ سرقہ کا قرینہ ہے۔
(۵) اسی طرح نشانیاں معلوم کر کے لقطہ واپس کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص نشانیاں بتا رہا ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے۔
مندرجہ بالا قرائین میں سزائے تعزیر ہو گی، حد ساقط ہو جائے گی، لیکن مجرم کو بری نہیں کیا جائے گا۔(۱)
لہٰذا شرعی وسیلہ اثبات یعنی نصابِ شہادت پورا نہ ہونے کی صورت میں دیگر ذرائع معلومات، جن میں مختلف قرائن شامل ہیں، اگر دستیاب ہوں تو حد ساقط ہو گی مگر تعزیری سزا دی جائے گی کیونکہ حد صرف قطعی یقینی عینی شہادت کی بنیاد پر ہی نافذ کی جا سکتی ہے، لیکن تعزیر قرائن کی بنیاد پر بھی نافذ کی جا سکتی ہے۔
علامہ ابن نجیمؒ فرماتے ہیں:
واجمعت الامۃ علی وجوبہ فی کبیرۃ لا توجب الحد او جنایۃ لا توجب الحد۔
’’امت کا اس پر اجماع ہے کہ تعزیر ہر ایسے کبیرہ گناہ پر ہو گی جہاں حد واجب نہ ہو، یا ایسا ضرر اور تعدی جہاں حد واجب نہ ہو۔‘‘(۲)
علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:
فینبغی ان یبلغ غایۃ التعزیر فی الکبیرۃ کما اذا اصاب من الاجنبیہ کل محرم سوی الجماع او جمع السارق المتاع فی الدار ولم یخرجہ۔
’’ہر اس جرم میں سخت ترین تعزیر ہے جو کہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہو، جیسے کوئی شخص کسی عورت سے ہم بستری کے سوا ہر طرح کا جنسی تلذذ حاصل کرے، یا چور مالک کے گھر سے سامان اکٹھا کرے مگر گھر سے باہر نہ نکال سکے۔‘‘(۳)
علامہ ابن نجیمؒ فرماتے ہیں:
کل من ارتکب معصیۃ لیس فیھا حد مقدر ثبت علیہ عند الحاکم فانہ یوجب التعزیر من نظر محرم ومس محرم و خلوۃ محرمۃ۔
’’جو شخص کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس میں حد مقرر نہ ہو اور جرم عدالت میں ثابت ہو جائے تو اس کو سزائے تعزیر دی جائے گی۔ جیسے نظربازی، چھیڑچھاڑ اور اجنبیہ کے ساتھ خلوت گزینی۔‘‘(۴)
ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:
والاصل فی وجوب التعزیر ان کل من ارتکب منکرا او اذی مسلما بغیر حق بقولہ او بفعلہ وجب علیہ التعزیر۔
’’بنیادی طور پر تعزیر کی سزا ہر اس شخص کے لیے واجب ہے جو کسی بھی منکر کا ارتکاب کرے، یا کسی مسلمان کو بلاوجہ ستائے، خواہ یہ ستانا زبان سے ہو یا عملی طور پر، اسے سزا کے طور پر تعزیر دی جائے گی۔‘‘(۵)
معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جسے شریعتِ اسلامیہ نے معصیت قرار دیا ہے، اگر وہ مستوجبِ حد نہ ہو تو اس میں سزائے تعزیر ہے، اور سزائے تعزیر میں اثبات کے لیے قرینہ قویہ کافی ہے۔ قرائن کی چند اور مثالیں پیش کر چکا ہوں۔ عصر حاضر میں آواز کی ریکارڈنگ، ویڈیو فلم، میڈیکل رپورٹ، اغتصاب، لڑکی کو اٹھا کر لے جانا یا بہلا پھسلا کر لے جانا، اور اسے خلوت میں اپنے ساتھ رکھنا، ہوٹل میں کمرہ لے کر رہنا، رجسٹر میں دونوں کا اندراج وغیرہ، یہ سب قرائن ہیں اور ان کی بنیاد پر سزائے تعزیر دی جا سکتی ہے۔
علامہ عبد الرحمٰنؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب میں تحریر فرماتے ہیں:
اتفق الائمۃ علی ان من وطی امراۃ اجنبیۃ فی ما دون الفرج بان اولج ذکرہ فی مغبن بطنھا ونحوہ بعیدا عن القبل والدبر لا یقام علیہ الحد و لکنہ یعزر لانہ اتی منکرا یحرمہ الشرع وقد حکم الامام علی علی من وجد مع امراۃ اجنبیۃ مختلیا بھا ولم یقع علیھا بان یضرب مائۃ جلدۃ تعزیرا لہ۔
’’تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جس شخص نے اجنبیہ کے ساتھ دخول کے سوا ہر طرح سے جنسی تلذذ حاصل کیا مثلاً پیٹ سے یا کسی اور مقام سے، لیکن قبل اور دبر سے مجتنب رہا، اس پر حد قائم نہ ہو گی۔ تاہم اسے تعزیری سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے شریعت کے ممنوع کردہ کام کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو، جو کسی اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں تھا لیکن اس نے وطی نہیں کی تھی، تعزیر کے طور پر سو کوڑے مارنے کا حکم صادر فرمایا۔‘‘(۶)
مشہور مصری محقق امام محمد ابو زہرہؒ فرماتے ہیں:
ویتحقق حق اللہ تعالیٰ فی کل حد سقط بالشبہۃ فاذا تزوج شخص مطلقتہ طلقۃ مکملۃ للثلاث و دخل بھا یقع الزواج باطلا ویکون الدخول حراما ولکن یسقط الحد بالشبہۃ ولیس معنی سقوط الحد الا تکون ثمۃ عقوبۃ قط بل یکون بالتعزیر ویکون ذلک حقا للہ تعالیٰ۔
’’ہر اس حد میں حق اللہ ثابت ہوتا ہے جو کسی شبہ کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہو۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی مطلقہ مغلظہ سے نکاح کر لیا اور اس سے ہم بستری کر ڈالی تو یہ نکاح باطل قرار پائے گا اور ہم بستری حرام، لیکن شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو گی۔ تاہم سقوطِ حد کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بالکل سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اسے حق اللہ کی خلاف ورزی میں سزائے تعزیر دی جائے گی۔‘‘(۷)
یعنی یہ سزا حقوق اللہ سے متعلق ہے، حقوق العباد سے نہیں۔ لہٰذا جہاں جہاں تعزیری سزا حقوق اللہ کی خلاف ورزی پر ہو گی وہاں حاکمِ مجاز کو اس سزا میں تخفیف یا معافی کا اختیار ہو گا، جبکہ حقوق العباد میں حاکمِ وقت کو کسی قسم کی معافی کا حق حاصل نہیں ہے۔
درجِ بالا اقتباس سے معلوم ہوا کہ اگر حدِ شرعی کسی معقول وجہ شرعی کے سبب ساقط ہو جائے تو مجرم کو جرم سے براءت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ دوسرے وسائل اثبات کی بنا پر اسے سزائے تعزیر دی جائے گی۔
سقوطِ حد کے باوجود سزائے تعزیر کے وجوب کی متعدد مثالیں فقہ اسلامی میں موجود ہیں۔
علامہ شہاب الدین شلبی حاشیہ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں رقم طراز ہیں:
ومن تزوج امراۃ لا یحل نکاحھا قال الکمال بان کانت ذوات محارمہ بنسب کامہ و بنتہ فوطیھا لم یجب علیہ الحد عند ابی حنیفۃ و سفیان الثوری و زفر وان قال علمت انھا علی حرام ولکن یجب علیہ المھر ویعاقب عقوبۃ ھی اشد ما یکون من التعزیر سیاسۃ لا حدا مقدرا شرعا اذا کان عالما بذالک وان لم یکن عالما بذلک لا حد علیہ ولا یعقوبۃ تعزیر۔
’’اگر کسی شخص نے کسی ایسی خاتون سے نکاح کیا جس سے نکاح حرام تھا، کمال ابن ہمام فرماتے ہیں مثلاً اپنی محرمات، ماں یا بیٹی سے، اور پھر ہم بستری کی تو اس شخص پر حد واجب نہ ہو گی۔ یہ موقف ابو حنیفہؒ، سفیان ثوری اور زفر کا ہے۔ اگرچہ وہ یہ اعتراف کرے کہ مجھے حرمتِ نکاح کا علم تھا۔ ایسے شخص پر موطوءہ کے لیے مہر واجب ہو گا اور مجرم کو تعزیرًا سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ سزا حد نہیں ہو گی بلکہ سیاستاً تعزیر شدید ہو گی جبکہ وہ حرمتِ نکاح کا علم رکھتا ہو۔ اور اگر اسے حرمت کا علم نہ ہو تو نہ حد ہو گی اور نہ تعزیر۔‘‘(۸)
اہلِ سنت کے مشہور امام مجاہدِ وقت علامہ ابن تیمیہؒ دمشقی اپنی شہرہ آفاق تصنیف السیاسۃ الشرعیۃ میں فرماتے ہیں:
اما المعاصی التی لیس فیھا حد مقدر ولا کفارۃ کالذی یقبل الصبی والمراۃ الاجنبیۃ او یباشر بلا جماع او یاکل ما لا یحل کالدم والمیتۃ او یقذف الناس بغیر الزنا او یسرق من غیر حرز او شیئا یسیرا او یخون امانۃ کولاۃ اموال بیت المال او الموقوف او یطفف المکیال والمیزان او یشھد بالزور او یلقن بالزور او یرتشی فی حکمہ او یحکم بغیر ما انزل اللہ۔
’’اور ایسے تمام جرائم میں جن میں نہ حدِ شرعی ہے اور نہ کفارہ، جیسے کسی بچے یا اجنبیہ کو (شہوت سے) بوسہ دینا، یا اس سے جماع کے سوا جنسی تلذذ حاصل کرنا، یا خون اور مردار جیسی حرام اشیاء کا کھانا، یا لوگوں پر زنا کے سوا تہمت لگانا، یا حرز کے بغیر چوری کا ارتکاب، یا چھوٹی موٹی چیز کی چوری، یا امانت میں خیانت، جیسے سرکاری فنڈز میں اہل کاروں کا خورد برد کرنا، یا اوقاف میں بددیانتی، یا اوزان و پیمائش میں بے ایمانی، یا جھوٹی گواہی دینا اور گواہوں کو جھوٹ بولنے کی تلقین کرنا، یا حکام کا رشوت لینا، یا شریعت کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔‘‘ (۹)
یہ تمام جرائم قابلِ تعزیر ہیں، مجرم پر حد نافذ نہیں ہو گی کیونکہ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی سزا متعین نہیں کی گئی۔ ایسے تمام جرائم کی سزا کی تعیین کا اختیار اسلامی حکومت کو ہے جو اپنے مقامی حالات کے مطابق قانون سازی کرے گی اور جس جرم کے لیے جو سزا متعین کرے گی وہ شرعاً درست ہو گی کیونکہ تعزیری سزاؤں کا مکمل اختیار اسلامی حکومت کو دیا گیا ہے۔
فقہ حنبلی کی مشہور کتاب الروض المربع میں موجبات سزائے تعزیر بیان کرتے ہوئے علامہ منصور تحریر فرماتے ہیں:
(والتعزیر) واجب فی کل معصیۃ لا حد فیھا ولا کفارۃ کاستمتاع لا حد فیہ و اتیان المراۃ المراۃ۔
’’تعزیر ہر اس جرم کی سزا ہے جس میں نہ حد ہو نہ کفارہ، جیسے ایسا جنسی تلذذ جس میں حد نہ ہو (یعنی دخول ثابت نہ ہو) اور عورت کا عورت سے استلذاذ۔‘‘(۱۰)
فقہاء اسلام نے جرائم کی بیخ کنی کے لیے صبی ممیّز کو بھی مستحقِ سزا قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ایسا بچہ جو نابالغ ہو مگر سمجھ والا ہو، مثلاً دس بارہ سال کا ہو، اگر وہ فاحشہ کا ارتکاب کرے تو اسے سزا دی جائے گی۔ نابالغ ہونے کی وجہ سے اسے صرف یہ رعایت ملے گی کہ اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اور سزائے تعزیر بالغ کی نسبت ہلکی ہو گی۔ لیکن بوجوہ عدمِ بلوغ اسے بری نہیں کیا جائے گا۔
فقہ حنبلی کی معروف کتاب منتہی الارادات کے مصنف فرماتے ہیں:
لا نزاع بین العلماء ان غیر المکلف کالصبی الممیز یعاقب علی الفاحشۃ تعزیرا بلیغا۔
’’تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نابالغ مگر سمجھدار بچہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔‘‘(۱۱)
تاہم یہ سختی اس کی عمر کے مطابق ہو گی، بالغ والی سخت سزا مراد نہیں ہے۔
دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:
و یجب التعزیر فی کل معصیۃ لا حد فیھا ولا کفارۃ کمباشرۃ دون الفرج وامراہ امراہ و سرقۃ لا قطع فیھا و جنایۃ لا قود فیھا کصفع و وکز ان الدفع و الضرب۔
’’تعزیر ہر اس جرم کے ارتکاب پر واجب ہے جس میں نہ حد ہو نہ کفارہ۔ جیسے شرم گاہ کے سوا جنسی تلذذ کا حصول، عورت کا عورت سے استلذاذ، ایسی چوری کا ارتکاب جس میں حد نہ ہو، ایسی جسمانی زیادتی جس میں قصاص نہ ہو، جیسے تھپڑ مارنا، دھکا دینا، یا مارنا۔‘‘(۱۲)
غور فرمائیے کہ باب التعزیر کتنا وسیع ہے کہ کسی کو دھکا دینا بھی جرم ہے اور تھپڑ مارنا بھی جرم۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو جرمِ زنا میں گرفتار کیا گیا، قانونی موشگافیوں اور حدیثِ رسول ’’الدرء والحدود بالشبھات‘‘ پر عمل کرتے ہوئے حد کسی وجہ سے ساقط ہو گئی مگر دیگر قرائن سے اس کا ارتکابِ جرم ثابت ہو گیا، تو باتفاق فقہاء اسلام اسے سقوطِ حج کی وجہ سے بری نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے تعزیری سزا دی جائے گی، کیونکہ سقوطِ حد مجرم کی براءت کی دلیل نہیں اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔
(۱) گیراج سے باہر سڑک کے کنارے یا کار پارکنگ سے گاڑی لے بھاگنا موجبِ حد نہیں کیونکہ سڑک اور پارک ایریا حرزِ مثل نہیں ہے۔
(۲) مسجد کے قالین، گھڑیاں یا پنکھے چوری کرنا۔
(۳) کسی اسٹیٹ بینک کی تجوری یا لاکرز سے رقم یا زیور اڑا لینا جبکہ زیور بینک کی ملکیت ہو۔
(۴) سکولوں، کالجوں کی لائبریریوں سے کتب کی چوری۔
(۵) فون کالوں اور بجلی کی چوری۔
(۶) سرکاری دفاتر سے ٹائپ رائٹر، فیکس مشینوں، ایئرکنڈیشنر، ریفریجریٹر یا دیگر سرکاری اشیا کی چوری۔
(۷) ریلوے ٹکٹوں کی چوری اور بغیر ٹکٹ سفر کرنا۔
(۸) اجنبیات کے ساتھ ڈانس کرنا۔
(۹) بیوی کی لونڈی سے جماع کرنا۔
(۱۰) باپ کا اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرنا۔
(۱۱) چوپایوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرنا۔
غرضیکہ ایسے بے شمار جرائم ہیں جن میں حد کی سزا نہیں۔ اگر سقوطِ حد کا فائدہ مجرم کو یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بری ہے تو پھر مندرجہ بالا جرائم میں سے کسی میں بھی حد نہیں۔ تو کیا مجرم کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ حد نہیں ثابت ہوتی؟ خدانخواستہ اگر اس قاعدے کو اپنا لیا جائے تو پھر اوباش لڑکوں اور فیشن زدہ لڑکیوں، مسجدوں سے چوریاں کرنے والوں، بد دیانت اور چور افسروں کے مزے ہوں گے۔ اس طرح کی سوچ ہی مِلّی تباہی کا باعث ہے چہ جائیکہ اسے قانون کا سہارا دیا جائے۔
یاد رکھئے! سقوطِ حد کا سبب شبہہ ہوتا ہے، چاہے وہ شبہہ فی الاثبات ہو، یا شبہہ فی الفعل، یا شبہ فی المحل، یا شبہ فی العقد۔ ان شبہاتِ ضعیفہ کی وجہ سے صرف حد ساقط ہو گی، تعزیر بہرحال باقی رہے گی۔ کیونکہ سقوطِ حد کے لیے معمولی شبہ بھی کافی ہے اور تعزیر کے لیے شرعی نصابِ شہادت اگر نہ بھی پورا ہو تو قرائن کی بنیاد پر، یا دو گواہوں، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے بھی تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔
قاعدہ یہ ہے کہ اسقاطِ حد کے لیے شبہہ ضعیفہ کافی ہے، اور اثباتِ تعزیر کے لیے قرینہ قویہ کافی ہے۔ سقوطِ حد سے وصفِ جرم ختم نہیں ہوتا۔ ارتکابِ حرام کا جرم باقی رہتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ سقوطِ حد میں شبہہ ضعیفہ پایا جاتا ہو۔ اگر شبہہ قویہ ہو تو البتہ سقوطِ حد کے ساتھ تعزیر بھی ساقط ہو جائے گی اور مجرم بری ہو جائے گا۔
امام ابو زہرہؓ فرماتے ہیں:
واذا کانت الشبہۃ ضعیفۃ فانھا تسقط الحد و لا تمحو وصف الحریمۃ فالتحریم ثابت واذا کانت عقوبۃ الحد سقطت فوراء ذلک عقوبۃ التعزیر و ینتقل العقاب من عقوبۃ مقدرۃ الی اخری غیر مقدرۃ۔
’’اگر شبہہ ضعیفہ ہو تو اس سے حد تو ساقط ہو گی لیکن وصفِ جرم ختم نہ ہو گا۔ حرمت باقی رہے گی۔ لہٰذا اگر حد ساقط بھی ہو گی تو اس کے بدلے تعزیری سزا باقی ہے، لہٰذا سزا حد سے منتقل ہو کر سزائے تعزیر میں بدل جائے گی۔‘‘(۱۳)
شبہہ ضعیفہ اور شبہہ قویہ اپنے نتائج کے اعتبار سے
ابو زہرہؓ فرماتے ہیں:
الشبھۃ القویۃ تمحو وصف الحریمۃ و یرتب علی ذلک سقوط العقوبۃ حتما والشبہۃ الضعیفۃ لا تمحو وصف الحریمۃ ولکنھا تسقط الحد فقط۔
’’شبہہ قویہ وصفِ جرم کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں سزا مکمل طور پر ساقط ہو جاتی ہے۔ شبہہ ضعیفہ وصفِ جرم کو ختم نہیں کرتا، صرف سقوطِ حد کا فائدہ دیتا ہے۔‘‘(۱۴)
شبہہ قویہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً بنیادی طور پر اثباتِ دعوٰی میں قانونی سقم موجود ہو، جیسے چوری کا مقدمہ تو قائم کر دیا گیا ہے مگر نہ تو مالِ مسروقہ برآمد ہوا اور نہ شہادتِ شرعیہ ہو۔ صرف ملزم کے مکان کے اندر پائے جانے اور نشاناتِ قدم اور نشاناتِ انگشت کی بنیاد پر چور قرار دیا جائے۔ شہادتوں میں تضاد ہو، کوئی گواہ وقوعہ کا وقت رات بتائے، کوئی صبح اور کوئی بعد ظہر۔ یہ تمام شبہات قویہ ہوں گے جن سے نہ صرف حد ساقط ہو گی بلکہ مجرم صاف بری ہو جائے گا۔
اس کے برعکس شبہہ ضعیفہ کی مثالیں یہ ہیں: مطلقہ ثلاثہ سے نکاح کر کے ہم بستری کرنا، سرکاری ٹائپ رائٹر یا فیکس مشین یا اور کوئی چیز دفتر سے بغرض مستقل قبضہ برائے تملیک اٹھا لے جانا، کسی شخص کا اجنبیہ کے ساتھ ایک بستر میں پایا جانا، یہ تمام جرائم ایسے ہیں کہ ان میں بوجہ شبہ کے حد جاری نہ ہو گی مگر سزائے تعزیر ضرور دی جائے گی، کیونکہ خلوت بالاجنبیہ معصیت ہے، گو زنا کے گواہ دستیاب نہ ہوں۔ ہر معصیت جرم ہے اور ہر معصیت قابلِ تعزیر ہے۔
حواشی
(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: الطرق الحکمیۃ لابن قیم، ص ۵۶۔ طرق الاثبات لمحمد ازحیلی ص ۵۱۸۔ التشریع الجنائی الاسلامی لعبد القادر عودہ ۔ ج ۵ ص ۳۳۹
(۲) بحر الرائق شرح کنز الدقائق ۔ ج ۵ ص ۴۶
(۳) رد المختار ج ۳ ص ۱۹۶ ۔ منحۃ الخالق علی بحر الرائق ۔ ج ۵ ص ۴۴
(۴) بحر الرائق ۔ ج ۵ ص ۴۶
(۵) ایضاً
(۶) الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ۔ ج ۵ ص ۱۰۲
(۷) العقوبۃ ۔ ص ۷۸ و ۷۹
(۸) حاشیہ شلبی علی تبیین الحقائق ۔ ج ۳ ص ۱۷۹
(۹) السیاسۃ الشرعیۃ فی اصلاح الراعی والرعیۃ لابن تیمیۃ ۔ ص ۱۱۱ و ۱۱۲
(۱۰) الروض المربع لمنصور یونس، ص ۴۹ ۔ انوار المسالک شرح عمدۃ السالک لاحمد نقیب المعری
(۱۱) منتہی الارادات ۔ ج ۳ ص ۳۶۱
(۱۲) ایضاً
(۱۳) العقوبۃ ۔ ص ۲۴۰
(۱۴) ایضاً
(جاری)
غیر منصوص مسائل کا حل ۔ فقہ اسلامی میں تجویز کردہ طریق کار
محمد عمار خان ناصر
مسلمانوں کی علمی میراث میں فقہ اسلامی کے نام سے جو ذخیرہ پایا جاتا ہے وہ اپنے اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے دو چیزوں سے عبارت ہے: ایک ان احکام کی تشریح و تعبیر جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں، اور دوسرے ان مسائل کے بارے میں دین کے منشا کی تعیین جن سے نصوص ساکت ہیں، اور جن کے حل کی ذمہ داری قرآن و سنت کے طے کردہ ضوابط کی روشنی میں امت کے علما کے سپرد کی گئی ہے۔ اپنے لغوی مفہوم اور قرآن و سنت کے استعمالات کے لحاظ سے فقہ کا لفظ ان دونوں دائروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تاہم اس کے اصطلاحی و عرفی مفہوم کے پیشِ نظر یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ فقہ کی اصل جولان گاہ غیر منصوص احکام کا دائرہ ہے، اسی لیے فقہی ذخیرے کا بیشتر حصہ انہی مسائل و مباحث کی تحقیق و تنقیح کے لیے خاص ہے۔
دوسرے تمام علوم و فنون کی طرح فقہ اسلامی بھی عہد بعہد ارتقا کے مراحل سے گزری ہے اور اس کے بنیادی و ذیلی اصولوں کی ترتیب و تدوین اور ان سے بے شمار جزئیات کی تفریع سینکڑوں اہلِ علم کی علمی کاوشوں کی مرہونِ منت ہے۔ اس سارے عمل میں، فطری طور پر، مختلف رجحانات اور فکری خصائص رکھنے والے مکاتبِ فکر بھی وجود میں آئے ہیں جن کے مابین پیدا ہونے والی مختلف النوع علمی بحثیں فی الواقع علم و نظر کی آبیاری کرنے اور ان کو جلا بخشنے والی ہیں۔ فقہا کی ان مسلسل اور گوناگوں کاوشوں کا ثمر یہ ہے کہ اسلامی فقہ نئے پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے ایک جامع، مربوط اور منضبط ضابطہ رکھتی ہے۔ مسلم فقہا نے نہایت دقتِ نظر کے ساتھ غیر منصوص احکام کو ان کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف دائروں میں تقسیم کیا اور ان کے حل کے لیے مختلف اطلاقی قواعد وضع کیے ہیں۔
جہاں تک فقہی آرا کے اختلاف کا تعلق ہے تو وہ علم و فکر کی دنیا کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ اس کے بغیر علوم و فنون نہ پھلتے پھولتے ہیں، نہ ان میں نئی نئی راہیں کھلتی ہیں اور نہ مختلف الجھنوں کی تنقیح کا سامان ہی فراہم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ تمام حلقہ ہائے فکر حیرت انگیز طور پر اپنا انتساب ایک ہی بنیادی سرچشمے کی طرف کرتے ہیں، اور اگر دقتِ نظر سے جائزہ لیا جائے تو ان سب کا استدلال و استنباط چند ایک ایسے کلی قواعد کے تابع ہوتا ہے جو ان کے مابین مابہ الاشتراک کی حیثیت رکھتے اور اس طرح اس غیر متناہی سلسلہ اختلافات میں رشتۂ اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ جہاں تک میں غور کر سکا ہوں، فقہی مکاتبِ فکر کے باہمی اختلافات بظاہر کتنے ہی وسیع الاطراف محسوس ہوتے ہوں، وہ بیشتر صرف اطلاق کے اختلافات ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ استنباط کے بنیادی اصول تو ایک ہی ہیں لیکن کسی خاص مسئلے میں ان کا اطلاق کرتے ہوئے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک فقہیہ اپنے علم و مطالعہ کی روشنی میں ایک اصول کا اطلاق درست سمجھتا ہے جبکہ دوسرے کے نزدیک بعینہ اس مسئلے میں کسی دوسرے اصول کا اطلاق بہتر ہوتا ہے۔
زیرنظر مقالہ میں، میں نے کوشش کی ہے کہ غیر منصوص مسائل کے حل کے لیے اسلامی فقہ میں تجویز کردہ طریق کار اور بنیادی قواعد کا ایک مختصر جائزہ پیش کروں اور ان کی توضیح چند ایسی مثالوں سے کروں جن میں ان قواعد کا اطلاق کیا گیا ہو۔ مثالوں کا انتخاب زیادہ تر جدید پیش آمدہ مسائل سے کیا گیا ہے تاکہ ایک طرف تو یہ بات واضح ہو کہ صدیوں پہلے طے ہونے والے یہ قواعد اپنی ہمہ گیری اور جامعیت کے لحاظ سے آج بھی قابلِ استناد ہیں، اور دوسری طرف یہ حقیقت بھی سامنے آئے کہ ان قواعد کی افادیت کا مدار اس بات پر ہے کہ جزئیات میں اجتہاد کا سلسلہ رکے بغیر جاری رہے اور فقہ اسلامی زمانے کے مسلسل ارتقا کا برابر ساتھ دیتی رہے۔
فقہی و علمی مسائل میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اہلِ علم کے مابین اختلافِ رائے کا واقع ہو جانا ایک بالکل فطری امر ہے۔ چنانچہ تمام علمی آرا کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ان آرا کو ترجیح دی ہے جو میرے ناقص فہم کے مطابق، ازروئے اصول و قواعد، اقرب الی الصواب ہیں۔
فقہ اسلامی کے ان قواعد کلیہ کا مطالعہ چار بنیادی عنوانات کے تحت کیا جا سکتا ہے:
۱۔ قیاس،
۲۔ احکام کی حکمت،
۳۔ مصالح، اور
۴۔ عرف
قیاس
شریعت کے احکام اکثر و بیشتر کسی خاص عِلّت پر مبنی ہوتے ہیں۔ قیاس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی منصوص حکم کو علت کی بنا پر ان صورتوں میں بھی ثابت کیا جائے جن میں یہ علت پائی جاتی ہے۔ فقہ اسلامی کے قدیم و جدید ذخیرے میں مسائل کی ایک بہت بڑی تعداد کے احکام اس اصول کے مطابق اخذ کیے گئے ہیں۔
جدید مسائل میں اس کی ایک مثال بندوق کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پھینک کر شکار کیے جانے والے جانور کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تیر کا نوک دار حصہ شکار کو لگا ہو اور اس سے جانور کا خون نکلا ہو تو وہ حلال ہے۔ اور اگر تیر چوڑائی والی جانب سے جانور کو لگا ہے اور اس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے تو چونکہ وہ ذبح نہیں ہوا بلکہ چوٹ لگنے سے مرا ہے اس لیے حرام ہے۔ تیر پر قیاس کرتے ہوئے علما نے بندوق سے شکار کیے جانے والے جانوروں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔
قیاس کا عمل دو پہلو رکھتا ہے:
ایک پہلو کا تعلق فہمِ نص سے ہے، یعنی اس میں کسی منصوص حکم کی علت متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ علت کی پہچان، اس کی شرائط اور اس کی تعیین کے مختلف طریقوں پر اہلِ اصول نے بحث کی ہے لیکن یہ تفصیل یہاں ہمارے موضوع سے خارج ہے۔
دوسرا پہلو اس حکم کے تعدیہ یعنی غیر منصوص صورتوں میں اس کے اطلاق سے متعلق ہے۔ کسی حکم کی علت کی درست تعیین کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ غیر منصوص مسائل پر اس کا اطلاق بھی درست ہو۔ اس ضمن میں فقہا نے متعدد عقلی قواعد وضع کیے ہیں جن میں سے چند بنیادی قواعد کا ہم اجمالاً یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔
(۱) پہلا ضابطہ یہ ہے کہ قیاس کے دائرے میں وہ احکام نہیں آ سکتے جن کے بارے میں مستقل نص موجود ہو۔ چنانچہ سفر کی حالت میں مغرب کی نماز کو ظہر، عصر اور عشا پر قیاس کرتے ہوئے قصر کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح خاوند اگر اپنی بیوی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگائے تو اس پر قذف کی حد جاری نہیں کی جا سکتی۔
(۲) دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ایسے منصوص احکام کو قیاس کا مبنی نہیں بنایا جا سکتا جو شریعت کے عام ضوابط کے تحت نہیں آتے بلکہ ان کی نوعیت مخصوص احکام کی ہے۔ اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں:
ایک یہ کہ وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو۔ چنانچہ ازواج کی تعداد میں جو رخصت قرآن مجید کی رو سے خاص طور پر آپ کے لیے ثابت ہے، اس میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ احناف نے اسی اصول پر ایسے شخص کے لیے جو کسی کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکا ہو، اس کی قبر پر نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔
دوسری یہ کہ اس کی نوعیت ایسی رخصت کی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے مخصوص اختیارات کے تحت دی ہو۔ روایات میں ابو بردہؓ کے لیے ایک سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی کی اجازت، اور سالم مولٰی حذیفہؓ کے لیے بڑی عمر میں حذیفہؓ کی بیوی کا دودھ پینے سے حرمتِ رضاعت کا ثبوت اسی نوعیت کے احکام ہیں۔ چنانچہ ان پر دوسرے کسی فرد کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
تیسری یہ کہ وہ حکم کسی مخصوص حالت سے متعلق اور کسی قید سے مقید ہو۔ اس صورت میں اس کو عام حکم بنانا درست نہیں ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشیؓ کی غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھائی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا انتقال ایک کافر ملک میں ہوا تھا اور اگرچہ مسلمان وہاں موجود تھے لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھتے اور اسلامی طریقے پر ان کی تدفین کرتے۔ چنانچہ نجاشیؓ پر قیاس کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی غائبانہ نماز جنازہ تو پڑھی جا سکتی ہے جن کی نماز جنازہ نہ پڑھی جا سکی ہو لیکن اس کو ایک عام عمل بنانا درست نہیں ہو گا۔
(۳) تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ قیاس کا مدار ظاہری مماثلت پر نہیں بلکہ حقیقی علت پر رکھنا چاہئے۔ جدید فقہی استنباطات نے اس اصول کی اہمیت کو نہایت موکد کر دیا ہے اس لیے کہ بالخصوص معیشت کے مسائل میں کیے جانے والے قیاسات کے نتائج بہت وسیع اور دور رس ہوتے ہیں، لہٰذا بیانِ احکام میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دو مثالیں ملاحظہ کیجئے۔
کرنسی نوٹ کی قوتِ خرید
قرض دے کر مدت کے عوض میں اصل سے زائد رقم لینا سود ہے جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ زمانہ قدیم میں سونا اور چاندی کو Medium of exchange یعنی اشیا کے تبادلہ کے لیے ذریعے کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے شریعت میں سونے اور چاندی کے قرض میں اصل سے زائد مقدار لینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جدید معیشت میں سونے اور چاندی کو یہ حیثیت حاصل نہیں رہی بلکہ ان کی جگہ کرنسی نوٹ نے لے لی ہے۔ کرنسی نوٹ کی قیمت چونکہ یکساں نہیں رہتی بلکہ مختلف معاشی عوامل کے تحت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نوٹ کی قوتِ خرید میں اس کمی بیشی کا مالی ادائیگیوں پر کیا اثر پڑے گا؟
مثال کے طور پر ایک شخص نے پانچ ہزار روپے کسی کو بطور قرض دیے اور قرض دیتے وقت ان کی قوتِ خرید ایک تولہ سونا تھی۔ کچھ عرصہ بعد جب مقروض نے قرض واپس کیا تو پانچ ہزار روپے کی قوتِ خرید کم ہو کر دس ماشے رہ گئی۔ اب کیا مقروض ہر حالت میں اتنی ہی مقدار میں نوٹ ادا کرے گا جتنے اس نے لیے تھے؟ یا ان کی قیمتِ خرید کا لحاظ کرتے ہوئے اتنے نوٹ دے گا جن سے ایک تولہ سونا خریدا جا سکتا ہو؟
ایک رائے یہ ہے کہ نوٹوں کی مقدار وہی رہنی چاہئے کیونکہ کرنسی نوٹ بھی سونا چاندی کی طرح ثمن ہیں، اس لیے جیسے سونا چاندی کے قرض میں کمی بیشی درست نہیں، اسی طرح نوٹوں کے قرض میں بھی کمی بیشی ناجائز ہے۔ تاہم اس قیاس میں محض ظاہری مماثلت کو دیکھتے ہوئے حقیقی علت سے صرفِ نظر کر لیا گیا ہے۔ اس لیے کہ سونا چاندی کی ایک حیثیت تو بلاشبہ یہی ہے کہ وہ اشیا کے تبادلہ کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ بذاتِ خود اپنی بھی ایک قیمت رکھتے ہیں۔ اور جب مقروض اصل مقدار میں سونا یا چاندی واپس کرتا ہے تو قرض خواہ کو کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے برخلاف کرنسی نوٹ کی بذاتِ خود کوئی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک فرضی قوتِ خرید کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے جس شخص نے دوسرے کو پانچ ہزار روپے دیے ہیں، اس نے نوٹوں کی شکل میں کوئی ایسی چیز اس کو نہیں دی ہے جو بذاتِ خود قیمت رکھنے والی ہو، بلکہ اس نے، درحقیقت، پانچ ہزار روپے کی قوتِ خرید اس کے حوالے کی ہے۔
لہٰذا عدل و انصاف کی رو سے ضروری ہے کہ قرض دینے والے کو اس کی قوتِ خرید پوری واپس ملے، چاہے نوٹوں کی مقدار میں بظاہر زیادتی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس صورت میں یہ زیادتی مدت کے عوض میں نہیں ہے، جو کہ حرمتِ سود کی اصل علت ہے، بلکہ اس نقصان کی تلافی کے لیے ہو گی جو اس عرصے میں نوٹ کی قوتِ خرید میں واقع ہو گیا ہے۔
صنعتی پیداوار
شریعت میں مالِ تجارت پر ڈھائی فیصد جبکہ زمین کی پیداوار پر دس فیصد یا پانچ فیصد زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ تجارت میں سرمایے کے محفوظ رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور سارے کا سارا سرمایہ ہر وقت معرض خطر میں ہوتا ہے، جبکہ زمین کی پیداوار میں نقصان اگر ہو سکتا ہے تو پیداوار میں ہو سکتا ہے، زمین، جو کہ پیداوار کا منبع ہے، بذاتِ خود محفوظ رہتی ہے۔ اس اصول پر دیکھئے، جدید معیشت میں کارخانوں اور فیکٹریوں کی مصنوعات اور مکانوں اور جائیدادوں کے کرایوں کو اگرچہ علما نے بالعموم مالِ تجارت شمار کیا ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ان کا الحاق مالِ تجارت کے بجائے مزروعات کے ساتھ کر کے ان پر دس یا پانچ فیصد زکوٰۃ عائد کرنی چاہئے کیونکہ ان میں بھی ذرائع پیداوار یعنی مشینیں اور اوزار وغیرہ بالعموم نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ دوسری رائے عقل و قیاس کے زیادہ قرین ہے۔
(۴) چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ بعض دفعہ علت سے قطعہ نظر کر کے محض احتیاطاً ایک چیز کو دوسرے کے قائم مقام قرار دے کر ایک کے احکام دوسری پر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ مثلاً غسل واجب ہونے کی اصل علت تو منی کا خروج ہے، لیکن احتیاطاً شرمگاہوں کے محض ملنے پر غسل واجب کیا گیا ہے۔ جدید مسائل میں اس سے ملتی جلتی صورت ٹسٹ ٹیوب کے استعمال میں پائی جاتی ہے۔ ٹسٹ ٹیوب کے طریقے میں مرد کی منی کو محفوظ کر کے اسے انجکشن کے ذریعے سے یا خود اسی ٹیوب کے ذریعے سے عورت کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس صورت میں عورت پر غسل واجب ہو گا یا نہیں؟ ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ غسل کا موجب درحقیقت منی کا ایسا دخول و خروج ہے جس میں جنسی لذت کا حصول بھی شامل ہو، اس لیے مذکورہ صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس صورت میں ازروئے علت نہیں لیکن ازروئے احتیاط غسل واجب ہو گا۔
احکام کی حکمت
شریعت کے تمام احکام خاص حکمتوں پر مبنی ہیں جن کا حصول ان احکام کے پورا کرنے سے مقصود ہوتا ہے۔ غیر منصوص مسائل میں بعض دفعہ عقلی لحاظ سے کئی پہلوؤں کا اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ دیکھنا چاہئے کہ احکام کی حکمت کی رعایت کس پہلو میں زیادہ ہے۔ اس اصول کا اطلاق حسبِ ذیل مسائل میں ہوتا ہے۔
نمازوں کے اوقات
ایسے مقامات جہاں بعض نمازوں کا وقت نہ ملتا ہو، مثلاً آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان گھنٹہ نصف گھنٹہ کا فاصلہ رہتا ہو، یا کئی کئی ماہ تک مسلسل دن یا رات رہتے ہوں، تو وہاں نمازوں کا حکم کیا ہے؟ بعض فقہا نے محض ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ فتوٰی دیا کہ چونکہ وقت نماز کے لیے شرط ہے اس لیے ان علاقوں میں وہ نمازیں فرض نہیں ہوں گی جن کا وقت نہیں ملتا۔ لیکن دوسری رائے، جو زیادہ معقول ہے، یہ ہے کہ شریعت کا اصل مطلوب ایک مخصوص وقت کے اندر پانچ نمازیں ہیں۔ اوقات ان نمازوں کے لیے محض علامت اور ظاہری سبب کی حیثیت رکھتے ہیں نہ کہ حقیقی سبب کی۔ اس لیے مذکورہ علاقوں میں بھی چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں ہی فرض ہوں گی اور ان کے اوقات قریبی علاقوں کے اوقات کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
ٹیلی ویژن سے نماز
نماز ایک زندہ روحانی عمل ہے اور اس میں قلبی کیفیات کو اصل مقصود کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے سے یگانگت اور وحدت کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ ٹیلی ویژن یا ریڈیو کے پیچھے پڑھنے میں نہیں ہو سکتیں، چنانچہ مذکورہ صورت میں نماز درست نہیں ہو گی۔
نس بندی
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں تبدیلی اور اس کے تقاضوں سے انحراف دین میں حرام ہے۔ مردوں کے عورتوں سے اور عورتوں کے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے کو اسی بنیاد پر حدیث میں قابلِ لعنت عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی اصول پر علما نے نس بندی کو حرام کہا ہے کیونکہ مردانہ صلاحیت اور اس کا جائز استعمال اس فطرت کا تقاضا ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس فطرت کو ختم کرنے کا اختیار انسان کو نہیں دیا گیا۔
حسن کے لیے سرجری
سرجری کے طریقوں میں ترقی کے باعث یہ ممکن ہو گیا ہے کہ انسان اپنی شکل و شباہت کو سرجری کی مدد سے ایک خاص حد تک اپنی پسند کے مطابق بنوا لے۔ اسلام کے نزدیک انسانوں کی صورت گری مختلف حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اچھی یا بری شکل دینے سے مقصود انسان کی آزمائش کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اس تقسیم کو قبول کرنا ہی بندگی کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اگر محض حسن پیدا کرنے کے لیے سرجری کروائی جائے تو یہ حرام ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کی خلقت انسانوں کی عام خلقت سے مختلف ہو، یا کسی حادثے کے نتیجے میں اصل شکل میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سرجری کے ذریعے سے اس کا علاج درست ہو گا۔
حد میں مقطوع الید کی پیوندکاری
شریعت میں حدود کا مقصد محض مجرم کو سزا دینا نہیں بلکہ اسے معاشرے کے لیے عبرت بنا دینا بھی ہے۔ لہٰذا سرجری کے ذریعے سے کسی ایسے شخص کے اعضا کو دوبارہ جوڑنا ناجائز ہو گا جس کا ہاتھ چوری میں یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ قصاص میں کاٹا گیا ہو۔
روزہ میں انجکشن
علما کے مابین انجکشن سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک انجکشن مطلقاً ناقض ہے اور بعض رگ میں لگائے جانے والے انجکشن کو ناقض اور دوسرے کو غیر ناقض قرار دیتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ انجکشن میں کون سی صورت پائی جاتی ہے، علما نے یہ بات بطورِ اصول تسلیم کی ہے کہ اگر جسم کے اندر داخل کی جانے والی کوئی چیز کسی منفذ کے ذریعے سے دماغ یا معدہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک روزے کا مقصد دراصل انسان کو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دینا ہے اور اس مقصد کے لیے شریعت میں اکل و شرب اور جماع کو ممنوع کیا گیا ہے۔ چونکہ علاج کی غرض سے کسی بھی قسم کی بیرونی دوا یا انجکشن استعمال کرنے سے اس مقصد پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے یہ چیزیں ناقضِ صوم نہیں ہو سکتیں۔ البتہ اگر کوئی شخص کوئی دوا یا انجکشن استعمال ہی اس غرض سے کرتا ہے کہ اس کے بدن کو تقویت پہنچے اور کمزوری محسوس نہ ہو، تو یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے، لہٰذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ وہ رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں۔
کیسٹ کو بے وضو چھونا
بعض علما کا خیال ہے کہ ایسی کیسٹ کو چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت ریکارڈ کی گئی ہو کیونکہ وضو کے حکم کا مقصد قرآن کا احترام ہے، اور احترام جیسے لکھے ہوئے قرآن کا ہونا چاہئے اسی طرح ریکارڈ کیے ہوئے قرآن کا بھی ہونا چاہئے۔ ہمارے خیال میں ادب اور احترام کا تعلق انسان کی داخلی کیفیات سے ہے، چونکہ کیسٹ پر قرآن ظاہری طور پر لکھا ہوا نہیں ہوتا اس لیے اس کو چھوتے ہوئے آدمی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے اور نہ وہ کوئی حجاب محسوس کرتا ہے، چنانچہ اس صورت میں باوضو ہونے کی شرط لگانا درست نہیں۔
ٹیپ ریکارڈر سے قرآن سننے پر سجدۂ تلاوت
علما کا خیال ہے کہ ٹیپ ریکارڈر سے تلاوت سننے پر سجدۂ تلاوت واجب نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سننے والا خود پڑھنے والے کی زبان سے قرآن سنے۔ ہمارے نزدیک سجدۂ تلاوت کی حکمت یہ ہے کہ آدمی ایسی آیات کو سن کر، جن میں سجدہ کی ترغیب دی گئی ہے، فورًا ان کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیت کسی کی زبان سے سنی گئی ہے یا ٹیپ ریکارڈر سے، اس لیے ہمارے نزدیک دونوں صورتوں کا حکم ایک ہونا چاہئے۔
مصالح
مصالح کے عنوان کے تحت مختلف ذیلی اصول مندرج ہوتے ہیں:
(۱) الدین یسر
پہلا اصول یہ ہے کہ مامورات میں، یعنی ایسی باتوں میں جن کا کرنا دین میں مطلوب ہے، حتی الوسع یسر اور آسانی کو ملحوظ رکھا جائے۔ ہمارے نزدیک حسبِ ذیل مسائل میں اس اصول کا اطلاق ہونا چاہئے۔
وِگ اور مصنوعی دانتوں کے ساتھ غسل
علما نے ایسے دانتوں میں جو مستقل طور پر لگا دیے گئے ہوں، اور ایسے دانتوں میں جن کو اتارا جا سکے، فرق کرتے ہوئے دوسری صورت میں غسل میں دانتوں کے اتارنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح سرجری کے بعض نئے طریقوں میں گنجے پن کے مریضوں کے سر پر ایک جھلی، جس پر بال لگے ہوتے ہیں، مستقل طور پر لگا دی جاتی ہے جو سر سے جدا نہیں ہو سکتی، علما نے اس طرح کی وگ کو بھی غسل سے مانع قرار دیا ہے۔ ہماری رائے میں یہ دونوں فتوے یسر کے خلاف ہیں۔
ناخن پالش کے ساتھ وضو اور غسل
ناخن پالش کے بارے میں علما کا موقف یہ ہے کہ اس کے ساتھ وضو درست نہیں کیونکہ اس کی تہہ (layer) ناخنوں تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہے۔ ہمارے نزدیک یسر کے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو جسم کے ساتھ اس طرح چپک جائے کہ اس کو الگ کرنے کے لیے رگڑنے یا کھرچنے کی ضرورت پڑے، اسے اصل جلد ہی کے حکم میں تصور کیا جائے۔ اس طرح ناخن پالش، پینٹ، یا تارکول وغیرہ کے جسم پر لگنے کی صورت میں ان کو اتارے بغیر وضو اور غسل درست ہو گا۔
(۲) الاصل الاباحۃ
دوسرا اصول یہ ہے کہ اشیا میں اصل اباحت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل درست ہے، اِلّا یہ کہ اس کے خلاف کوئی ممانعت شریعت میں وارد ہوئی ہو۔ اس اصول پر حسبِ ذیل امور جائز قرار پاتے ہیں:
اعضا کی پیوندکاری
علما کے ایک گروہ کے خیال ہے کہ ایک انسان اپنا کوئی عضو اپنی زندگی میں یا موت کے بعد کسی دوسرے شخص کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا جسم درحقیقت اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے اسے اپنے جسم پر اس نوعیت کا تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علما کے دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ اعضا کی منتقلی سے انسانوں کا فائدہ متعلق ہے کیونکہ اس طریقے سے کئی مریض مرض سے نجات پا لیتے ہیں اور بعض صورتوں میں ان کی زندگی بھی بچائی جا سکتی ہے، اس لیے یہ طریقہ درست ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری رائے درست ہے۔
ٹسٹ ٹیوب
ٹسٹ ٹیوب کی مدد سے بعض بے اولاد جوڑوں کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہو گا، بشرطیکہ بچے کی تولید میں مادہ ایسے مرد و عورت ہی کا استعمال کیا جائے جو شرعی طور پر میاں بیوی ہیں۔
چٹ فنڈ یا کمیٹی
ہمارے معاشرے میں عام لوگوں نے سہولت کی غرض سے کمیٹی کے نام سے قرض کا ایک طریقہ رائج کیا ہے جس میں تمام شرکا ہر ماہ رقم کی ایک متعین مقدار ادا کرتے ہیں اور جمع شدہ رقم باری کے مطابق کسی ایک رکن کو دے دی جاتی ہے۔ اس طرح تمام شرکا اپنی اپنی باری پر اپنی رقم پوری کی پوری اکٹھی وصول کر لیتے ہیں۔ بعض اہلِ علم نے اگرچہ اس کو غلط قرار دیا ہے لیکن ہمارے نزدیک اس طریقے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اس کا ایک دوسرا طریقہ جس میں شرکا کو اپنی ادا کردہ رقم سے کم یا زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، صریحاً ناجائز ہے۔
ممسک حیض ادویہ
حج کے ایام میں تمام افعالِ حج کو اپنے مقرر وقت پر انجام دینے کے لیے اگر خواتین ایسی ادویہ استعمال کریں جو وقتی طور پر حیض کے خون کو روک دیں تو کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد تنہا روزے رکھنا نفسیاتی طور پر مشکل ہو گا تو وہ رمضان ہی میں روزے رکھنے کے لیے ایسی ادویہ استعمال کر سکتی ہے۔
(۳) الضرورات تبیح المحظورات
تیسرا اصول یہ ہے کہ شریعت کے حرام کردہ امور اضطرار کی حالت میں، ضرورت کے مطابق جائز قرار پاتے ہیں۔ اس کا اطلاق حسبِ ذیل صورتوں میں ہوتا ہے:
بینک کی ملازمت
بینک کی بنیاد چونکہ سودی کاروبار پر ہے، اس لیے حدیث کی رو سے اس میں کسی بھی درجے میں شرکت حرام ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ معاش نہ ہو جس سے اس کے روز مردہ اخراجات پورے ہو سکتے ہوں تو وہ متبادل ذریعہ معاش میسر ہونے تک بینک کی ملازمت کر سکتا ہے۔
سودی قرض لینا
سود پر قرض دینا اور لینا، اصولی طور پر، دونوں حرام ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنی روز مرہ ضروریات (خوراک اور لباس) پورا کرنے سے بھی عاجز ہو تو وہ ضرورتاً سود پر قرض لے سکتا ہے۔
ٹیکس اور سود میں سود کی ادائیگی
اگر کسی شخص کے پاس سود کسی طریقے سے آجائے تو وہ اسے اپنے کسی استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے اس کو اپنی مِلک سے نکال دینا واجب ہے۔ البتہ اگر اس پر کسی ایسے ٹیکس کی ادائیگی واجب ہو جو حکومت نے ناجائز طور پر عائد کیا ہے، یا اس نے مجبورًا سود پر قرض لیا ہو تو وہ سود کی مد میں حاصل ہونے والی رقم کو ٹیکس اور سود کی ادائیگی میں استعمال کر سکتا ہے۔
پوسٹ مارٹم
انسانی جسم کی چیر پھاڑ ناجائز ہے، لیکن علاج یا دیگر ضرورتوں کے تحت اس کی اجازت ہے۔ طبِ جدید میں موت کی وجوہ اور اس طرح کے دیگر معاملات کی تفتیش کے لیے مُردے کے جسم کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ضرورت کے اصول کے تحت یہ درست ہو گا۔
(۴) المشقۃ تجلب التیسیر
چوتھا اصول یہ ہے کہ شریعت نے بعض احکام میں جو شرائط و قیود لاگو کی ہیں، اگر کسی موقع پر ان کی پابندی کرنے سے حرج لاحق ہوتا ہو تو ان کی رعایت ضروری نہیں رہے گی۔
طویل الاوقات علاقوں میں روزہ
ایسے علاقے جہاں ایک طویل عرصہ تک مسلسل دن اور پھر رات کا سلسلہ رہتا ہے، روزے کے اوقات قریبی علاقوں کے اوقات کے مطابق طے کیے جائیں گے کیونکہ اس قدر طویل عرصہ تک روزہ رکھنا ناممکن ہے۔
ٹرین، ہوائی جہاز وغیرہ میں نماز
نماز میں قیام کرنا اور قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ تاہم ٹرین، ہوائی جہاز یا بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے اگر قیام کرنے یا قبلہ رخ ہونے کا التزام کرنے میں دِقت ہو تو یہ شرائط ساقط ہو جائیں گی اور بیٹھ کر کسی بھی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہو گا۔
حالتِ حیض میں بیت اللہ کا طواف
بیت اللہ کے طواف کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر ایامِ حج میں عورت کو حیض آ جائے تو وہ پاک ہونے کے بعد ہی طوافِ زیارت کر سکتی ہے۔ لیکن آج کل اس پر عمل کرنا ممکن نہیں کیونکہ حکومتِ سعودیہ کی جانب سے حاجیوں کو مخصوص دنوں کا ویزا جاری کیا جاتا ہے اور ان کی واپسی کی تاریخ کئی دن پہلے مقرر ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس صورت میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہی طوافِ زیارت کر سکتی ہے۔
حالتِ حیض میں تلاوتِ قرآن
حیض کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کا پڑھنا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی عورت کسی مکتب میں معلّمہ یا طالبہ ہو تو ظاہر ہے کہ زیادہ دنوں تک چھٹی کرنے سے تعلیمی سرگرمیوں میں حرج واقع ہوتا ہے، لہٰذا ایسی خواتین کے لیے حالتِ حیض میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا جائز ہو گا۔
(۵) ما ادی الی المحظور فھو محظور
اس اصول کا دوسرا نام سدِ ذرائع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور جو کسی ممنوع کام کا ذریعہ بنتے ہوں، ناجائز ہیں۔
جدید مسائل میں اس کی نظیر مانع حمل ادویہ اور آلات کی عام فراہمی ہے۔ علما نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ معاشرے کو زنا سے محفوظ رکھنے کے لیے داخلی پاکیزگی کی تربیت کے ساتھ ساتھ خارجی موانع بھی برقرار رہنے چاہئیں اور شریعت نے اسی غرض سے پردہ وغیرہ کے احکام دیے ہیں۔ زنا کے بارے میں انسانی جبلت اور معاشرتی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں اصل مانع کی حیثیت بدنامی کے خوف کو حاصل ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس مانع کو معاشرے میں برقرار رکھا جائے ورنہ زنا پر کنٹرول ناممکن ہو جائے گا۔ مانع حمل ادویہ اور آلات کی سرعام فراہمی نے خود ہمارے معاشرے میں بھی، جہاں اعتقادی طور پر زنا کو حرام سمجھا جاتا ہے، اس خوف کو ختم کر دیا ہے اور زنا پہلے کی نسبت کہیں زیادہ عام ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مانع حمل ادویہ اور آلات کی فراہمی کو محدود کیا جائے اور شادی شدہ جوڑوں کے علاوہ دوسروں کو اس کی فراہمی پر پابندی عائد کی جائے۔
(۶) یختار اھون الشرین
اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صورت حال میں دو غلط راستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے تو کم مفاسد والے راستے کو اختیار کیا جائے۔ اس کی مثالیں حسبِ ذیل ہیں:
ظلم کے نظام میں شرکت
کسی ایسے اسلامی یا غیر اسلامی ملک میں جہاں ظلم کا نظام ہو، کاروبارِ حکومت میں شریک ہونے کی صورت میں، ظاہر ہے آدمی کو بہت سے ناجائز کام کرنے پڑیں گے، چاہے وہ دل سے ان کے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ یہی صورت ہمارے معاشرے میں تجارت کی ہے۔ لیکن اگر ان میدانوں میں شرکت کو نیک لوگوں کے لیے بالکل ممنوع قرار دیا جائے تو یقیناً زیادہ بڑے مفاسد پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان میدانوں میں آنے کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی جائے جو طبعاً برائی کو ناپسند کرتے ہوں، اور اس کو مجبوری کے دائرے میں رکھتے ہوئے باقی امور میں ملک و قوم کی خدمت انجام دے سکیں۔
جڑواں بہنوں کا نکاح
اگر دو عورتیں اس طرح پیدا ہوئی ہوں کہ ان کے اعضا ایک دوسرے کے ساتھ ناقابلِ انفصال طریقے پر جڑے ہوئے ہوں تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ عقلاً اس میں تین احتمال ہیں: یا تو وہ دونوں مجرور رہیں، یا دونوں کا نکاح دو الگ الگ مردوں سے کر دیا جائے، اور یا دونوں کو ایک ہی مرد کے نکاح میں دے دیا جائے۔ ان میں سے تیسری صورت میں پہلی دو صورتوں کی بہ نسبت کم قباحت اور ضرر پایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اسی کو اختیار کیا جائے۔
عرف
قانون سازی میں معاشرے کے عرف و رواج کی اہمیت دنیا کے تمام قدیم و جدید قانونوں میں مسلّم ہے اور فقہ اسلامی میں بھی اسے ایک مستقل ماخذِ قانون کی حیثیت دی گئی ہے۔
(۱) عرف کے ضمن میں پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ نصوصِ شریعت اور اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو تو معتبر ہو گا۔ ہر معاشرہ اپنی ضروریات اور حالات کے لحاظ سے افرادِ معاشرہ کے حقوق کی حفاظت اور معاملات کو بسہولت انجام دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا رہتا ہے۔ اس نوعیت کے تمام احکام اسلامی فقہ میں حجت مانے جاتے ہیں، اِلّا یہ کہ وہ شریعت کی طے کردہ حدود و مقاصد سے ٹکراتے ہوں۔
اس کی ایک مثال حقوق کی وہ قسم ہے جسے فقہا حقوقِ عرفیہ کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایسے حقوق جو نص سے ثابت نہیں لیکن کسی خاص عرف یا ماحول میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے ثبوت کا مدار عرف پر ہے، اس لیے زمان و مکان کے اختلاف سے یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ حقوقِ عرفیہ کی چند نئی صورتیں جو ہمارے زمانے میں رائج ہیں اور جنہیں اہلِ علم نے تسلیم کیا ہے، حسبِ ذیل ہیں:
پگڑی
کرایہ داری کے مروّج طریقوں میں جائیداد کا مالک کرایہ دار سے کرایہ کی رقم کے علاوہ ایک متعین رقم پگڑی کے نام سے الگ سے وصول کرتا ہے، جس کا مقصد کرایہ دار کی جانب سے جائیداد کی حفاظت اور بروقت جگہ خالی کرنے کی ضمانت حاصل کرنا ہوتا ہے، علماء نے اس صورت کو درست تسلیم کیا ہے۔
حقِ تالیف و ایجاد و حقِ طباعت
جدید قوانین میں کسی کتاب کے مصنف یا ناشر کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ ان سے اجازت لیے یا ان سے معاہدہ کیے بغیر کوئی دوسرا شخص یا ادارہ اس کتاب کو شائع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض مخصوص ایجادات کے موجدین کی اجازت کے بغیر ان کی تیاری اور فروخت نہیں کی جا سکتی۔
رجسٹرڈ نام اور ٹریڈ مارک
کمپنیاں مختلف کاروباری فوائد کی خاطر مخصوص نام اور ٹریڈمارک رجسٹرڈ کرا کر اپنی مصنوعات کی تشریح کرتی ہیں اور اس طرح صارفین میں اس نام کی ایک reputation بن جاتی ہے۔ جدید قوانین کی رو سے کسی دوسری کمپنی کو اس نام یا ٹریڈ مارک کے ساتھ مصنوعات بنانے یا بیچنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے اصل کمپنی کو کاروباری لحاظ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی دھوکا ہوتا ہے۔
(۲) دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ عرف اگر نصوصِ شریعت یا اس کے مزاج کے خلاف ہو تو معتبر نہیں ہو گا۔ چنانچہ جدید دور میں سود، جوئے اور دیگر شرعی محرمات کی تمام صورتوں کو اہلِ علم نے بالاتفاق حرام قرار دیا ہے، اگرچہ وہ معاشرے بہت عام ہو گئی ہیں۔
(۳) تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ عرف اگر قیاسِ خفی کے معارض ہو تو عرف کو ترجیح ہو گی۔
اس کی ایک مثال تعطیلات کی اجرت ہے۔ قیاس کی رو سے تو آدمی کو صرف ان دنوں کی اجرت لینی چاہئے جن میں اس نے خدمت انجام دی ہے، لیکن چونکہ بالعموم اداروں، محکموں اور کمپنیوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ ملازمین کو تعطیلات کی اجرت بھی دی جاتی ہے، اس لیے یہ طریقہ درست مانا گیا ہے۔
اسی طرح ہمارے ملک میں یہ طریقہ رائج ہے کہ پرنٹنگ پریس چند نسخوں سے لے کر ایک ہزار یا گیارہ سو تک نسخوں کی اشاعت کا ایک ہی معاوضہ وصول کرتا ہے۔ بظاہر دس یا بیس نسخوں اور ایک ہزار نسخوں میں بڑا تفاوت ہے اور از روئے قیاس طباعت کے معاوضے میں بھی فرق ہونا چاہئے، لیکن چونکہ یہ طریقہ عام رائج ہے اور عرفاً اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، لہٰذا قیاس ناقابلِ التفات ہو گا۔
(۴) چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ عرف کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔
مثلاً کرنسی نوٹ جب نیا نیا متعارف ہوا تو اس وقت عرف کے لحاظ سے اس کی حیثیت ایک وثیقہ اور ضمانت کی تھی، چنانچہ علما نے اس کے لین دین پر وثیقہ کے فقہی احکام جاری کرتے ہوئے فتوٰی دیا تھا کہ ان سے زکوٰۃ یا قرض وغیرہ اس وقت تک ادا نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحبِ حق بینک سے اصل زر وصول نہ کر لے۔ لیکن اب نوٹ کی حیثیت عرفی ثمن کی ہے اور کوئی شخص ان کو وثیقہ یا اصل رقم کی ضمانت نہیں سمجھتا، لہٰذا ان پر اس عرفی ثمن کے احکام جاری ہوں گے اور ان کے ادا کرنے سے قرض، زکوٰۃ اور دوسری ادائیگیاں، حقیقی ادائیگیاں سمجھی جائیں گی۔
انسانی علم کے ارتقا نے جو نئی سہولیات مہیا کی ہیں ان سے استفادہ بھی ہمارے نزدیک اسی ضمن میں آتا ہے۔ چنانچہ رؤیتِ ہلال میں جدید سائنسی آلات سے، جرائم کی تفتیش میں تربیت یافتہ کتوں اور انگلیوں کے نشانات سے، اور قتل و زنا کے مقدمات کی تحقیق میں پوسٹ مارٹم، ڈی این اے ٹیسٹ اور طبی معائنے کی دوسری صورتوں سے مدد لینا اور ان پر اعتماد کرنا بالکل درست ہو گا۔
اس جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی فقہ نئے پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے ایک جامع، مربوط اور منضبط ضابطہ رکھتی ہے۔ اس ضمن میں فقہا کے وضع کردہ قواعد مضبوط علمی و عقلی اساسات پر مبنی ہیں اور، چند جزوی اختلافات سے قطع نظر، فقہا کے مابین ہمیشہ مسلّم رہے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد خود قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور فقہا صحابہؓ کے اجتہادات میں موجود ہے۔ ان قواعد کی جامعیت عقلی استقرا کے لحاظ بھی بالکل قطعی ہے، اور ان چودہ صدیوں میں ان کے عملی استعمال نے بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ قیامت تک انسانی زندگی کو پیش آنے والے ہر نشیب و فراز کا سامنا کرنے اور ہر قسم کے مسائل کے حوالے سے دین کا منشا متعین کرنے کے لیے کافی و شافی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ علم بالصواب۔
مراجع
(۱) اصول الفقہ: خضری بک
(۲) الوجیز فی اصول الفقہ: عبد الکریم زیدان
(۳) فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر: مولانا محمد تقی امینی
(۴) عرف و عادت اسلامی قانون میں: ساجد الرحمٰن صدیقی
(۵) فقہ اسلامی میں نظریہ سازی: ڈاکٹر جمال الدین عطیہ، مترجم: مولانا عتیق احمد قاسمی
(۶) اسلامی قانون کے کلیات: ڈاکٹر عبد المالک عرفانی
(۷) جدید فقہی مسائل: خالد سیف اللہ رحمانی
(۸) فقہی مقالات: مولانا محمد تقی عثمانی
(۹) جدید فقہی مباحث: مرتب، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی
(۱۰) مقالاتِ سواتی: مولانا صوفی عبد الحمید سواتی
(۱۱) اسلام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد فاروق خان
(۱۲) سیاست و معیشت: جاوید احمد غامدی
محترم نعیم صدیقی صاحب کا مکتوب گرامی
نعیم صدیقی
(نعیم صدیقی صاحب ہمارے ملک کے بزرگ دانش ور ہیں جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ کے قریبی ساتھیوں اور جماعتِ اسلامی کے فکری مربیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک مکتوب میں محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کے ساتھ گزشتہ دنوں ہونے والی مدیر الشریعہ کی تحریری گفتگو کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کے سارے ارشادات سے ہمیں بھی اتفاق ہو، مگر ایک صاحبِ فکر و نظر اور بزرگ دانش ور کے خیالات و تاثرات سے قارئین کو محروم کرنا مناسب خیال نہ کرتے ہوئے یہ مکتوب شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ)
مکرمی مولانا زاہد الراشدی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
’’اشراق‘‘ میں جناب جاوید احمد غامدی جو گل کتر کر گلشنِ اسلام کی شان دکھا رہے ہیں، میں ان سے بلاتعصب مستفید ہوتا ہوں، مگر ان میں اور ان کے تیار کردہ ہم سفرانِ فکر و دانش میں بعض جھول ایسے ہیں کہ دل مسوس کر رہ جاتا ہوں۔
ایک تو ان میں بے شمار حلقہ ہائے فکر و نظرِ اسلامی میں سے ذرا ابھر کر کچھ نئی راہیں نکالنے کا معاملہ ہے، وہ ان کی خاص ضرورت ہے۔ وہ تمام نصوص اور معاملات اور نقطہ ہائے نظر سے خوردبینی نگاہ کے ساتھ ایسے پہلو یا گوشے نکالتے ہیں کہ ایک متوسط قاری یہ تاثر لے سکتا ہے کہ وقت کا کوئی بڑا مجتہد پیدا ہوا ہے جو عام سی باتوں میں سے ایسے ایسے لطیف نکتے نکالتا ہے کہ سر پھر جاتا ہے۔ مگر اہلِ علم و تحقیق اگر بغور تجزیہ کریں تو بس ایک طرح کا ہپناٹزم ہے۔ اسی کو آپ نے تفرد کہا ہے اور اس تفرد کے بغیر کوئی نوخیز آدمی جگہ بنا ہی نہیں سکتا۔ زور ہمیشہ کسی مروّج و معروف مسئلے میں اختلافی دراڑ پیدا کرنے کا ہے۔ مشکل یہ کہ اس تفرد کو کسی طرف سے مسلّمہ علمی شخص یا ادارے کی سند ملنی چاہئے۔ اس سند کے لیے وہ فورًا اصلاحی صاحب کی طرف لپکتے ہیں۔ ایک متعین مرکزِ استفادہ، چند مسائلِ تفرد، یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ایک نئے مرکزِ علم و فکر کا قیام عمل میں آتا ہے۔
میں نے آپ کی جرأت مندی کو سراہا کہ اکیلے میدان میں اترے اور دوسری طرف سے تین چار نوجوانوں کا جتھا آپ کے پیچھے لگ گیا، مگر کہیں خم آپ نے بھی نہیں کھایا۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں آپ کی مدد کو نکلوں، مگر کم علمی الگ، میری صحت کی کشتی عرصہ سے گرداب میں ہے۔
جہاد کے موضوع پر مجھے بالکل اپنے طرز پر کچھ کہنا ہے مگر بے بس ہوں، اسی طرح دوسرے مسئلے۔ مثلاً اس وقت کہیں بھی اسلامی قانون، اسلامی عدالتیں اور ان پر اسلامی حکومت کا انضباط موجود نہیں ہے۔ کتنے ہی فیصلے شریعت کے خلاف آتے ہیں۔ پبلک کے پاس جوابی دباؤ کا کوئی راستہ نہیں بجز دارالافتا کے۔ آپ نے اسے بھی پابند کر دیا کہ کسی بد راہ قانون و عدالت کی مکھی پر مکھی مارنے کے سوا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کئی علاقوں میں بعض مدتوں میں سرکاری قانون کو فیل کرنے اور شرعی قانون کو نافذ کرنے کے انتظامات کیے گئے اور عجیب عجیب کامیابیاں حاصل ہوئیں۔
جاوید صاحب میرے لیے بمنزلہ عزیز کے ہیں، میں ان کی صلاحیتوں کا متعرف بھی ہوں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ذہانت و صلاحیت ایسا خزانہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ بات اپنے لکھنے پڑھنے کے زمانے میں میرے سامنے رہتی تھی۔ شیطان کی یہ دل چسپی ویسی ہی ہے جیسی حسن و شباب کا خزانہ کہیں پائے تو وہاں شیاطین ہر لحظہ چکر لگائیں گے۔ اسی طرح دولت اور اقتدار کے لیے ان کی دل چسپیاں ہیں۔
اس بارے میں غفلت کی وجہ سے وہ بعض بڑی غلطیوں کے مرتکب ہوئے ہیں: ایک یہ کہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، اور سیاست کاری کے تینوں کام ایک سلسلے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے الگ الگ تنظیمیں ہوں جو ایک دوسرے کے تسلط سے آزاد ہوں۔ دوسری بڑی غلطی یہ کہ اقیمو الدین کی تشریح انہوں نے ایسے انداز سے کی کہ مساعئ اقامتِ دین کے جذبے کو ختم کرنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس سلسلے میں دلائل سے مسلح ہوں، مگر وہی نہ وقت، نہ ہمت۔ لہٰذا جو کچھ ہوتا ہے، دیکھتا ہوں۔
’’اشراق‘‘ کے حاشیے پر پنسل سے بہت ہی رف سے اشارات لکھتا ہوں کہ شاید ان کی بنیاد پر کچھ لکھنا ممکن ہو۔ مگر نئے شمارے نئے مباحث لے کے آجاتے ہیں، لہٰذا مسلک یہ بنا کہ ؏
صورتِ آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہ
آپ سے زندگی بھر نہ شرفِ ملاقات حاصل ہوا، نہ مراسلت کا تعلق، بس آپ جیسے معروف آدمی پر نگاہ ضرور رہی اور کبھی آپ کی تحریریں پڑھیں بھی۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ سے دین کی خدمت مزید لے۔
نیاز کش
نعیم صدیقی
۲۹ جون (شب) ۲۰۰۱ء
پسِ نوشت
یہ حضرات بغداد والے ان علاماؤں کی روش پر بحثوں میں پڑے، وقت کی آفات سے ایسے غافل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تاتاری مسلمانوں اور ان کی حکومتوں کو برباد کرتے ہوئے بغداد کی طرف آ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ کوئی تدبیر آنے والی تباہی کے تدارک کے لیے کرتے، انہیں اپنی بحثوں سے فرصت نہ تھی، یہاں تک کہ سب صفایا ہو گیا، نہ عِلم باقی رہا نہ عَلم۔
یہ لوگ آیات و روایات کے تجزیے میں محو ہیں اور اس سے بالکل بے خبر کہ بالکل غیر متوقع طور پر کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں جن میں جہاد کی نئی شکلوں کی ضرورت ہے۔ اشراقیوں کا اساسی علم تو حضرت عثمانؓ کے دور ہی کے معاشرے پر بڑی مشکل سے لاگو ہوتا ہے۔ حضرت علیؓ کے دور میں تو شرائطِ جہاد کا معیاری اطلاق ممکن ہی نہیں رہتا۔ اور آج ۔۔۔ آج یہ صورت نہیں کہ ایک مرکزی اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کے احکام یا اشاروں سے حملہ آوروں یا اسلام دشمن فاتحین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور ایسا کوئی مرکز ہوتا بھی تو آج کے دور میں اندر ہی اندر اس کے معدے اور اس کی رگِ جاں کو ہک لگا کر دشمن قوتیں باندھ چکی ہوتیں۔ پھر مسلمان کیا کرتے؟
جب مغربی امپریلسٹ طاقتیں نوآبادیات سازی کے لیے مسلم اور ایشیائی و افریقی حکومتوں کا شکار کرنے نکلیں تو یہ مجنونانہ مسابقتی یورش ہر طرف سے جابجا شروع ہو گئی۔ کون سی قوم کہاں ہجرت کر کے جاتی اور کون سی حکومت کس کی مدد کو پہنچتی؟ بیرونی حملہ، جبر اور اچانک اس کا سامنا، اس میں جاسوسیوں، غداریوں اور ضمیروں کی خریداری کے ایسے ایسے عوامل کا ہونا کہ ایک حکومت کے سالم یا جزوی طور پر بچ نکلنے کی امیدیں ہوتیں؟ اور عوام کے لیے کوئی منظم جدوجہد کی رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں ان کی خوں ریزی اور سلب و نہب اور غلام سازی و بیگار کا ایک ایسا سلسلہ چلتا کہ کوئی راہِ فرار نہ تھی۔ ان سے یہ کہنا کہ صبر کرو، گویا کسی جماعتِ نبوی کے پابندِ نظم لوگوں کا سابقہ کسی خلیفہ غیر راشد یا حاکمِ مطلق کے مظالم سے تھا۔
دین کی نئی تعبیریں کرنے والے نوجوانو! تم تو بدلتے ہوئے سوشل، حکومتی اور بین الاقوامی سسٹم اور اس میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھتے۔ اور معیاری جہاد نہ سہی، کسی کم تر درجے کے جہاد کے لیے اجتہاد کرتے۔ میں مثالیں دینے کا نہ وقت رکھتا ہوں نہ قوت، مگر میں توجہ دلاؤں گا کہ جو کام بغداد یا کوئی اور مقام نہ کر سکا، اسے مصر میں سلطان ۔۔۔ نے آغاز کر کے ۔۔۔ تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ وہ پھر دم دبا کر بھاگے اور پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا، سارا خطۂ اسلامی ظالموں سے پاک ہو گیا۔
میں کہتا ہوں کہ آپ اسے شبہ جہاد کہہ سکتے ہیں، اضطراری جہاد کہہ سکتے ہیں، مجددانہ جہاد کہہ سکتے ہیں، اس کی نئی تعریفیں وضع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے بلکہ قرونِ اولیٰ کے معاشرے کو برقرار فرض کر کے سارے احکام کا اجرا اسی کے مطابق کرنا ہے تو پھر زیادہ بحثوں کی کیا ضرورت؟ کرتے رہیے۔ دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجئے۔ آپ کا سرچشمۂ علم جب ایک خاص شخصیت ہے، ہر تان اسی پر توڑتے ہیں، تو پھر آپ اسی کنویں میں گھومتے رہیے۔ مولانا زاہد الراشدی یا کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس نیک کام میں دخل دیں۔
ہماری مشترک دل چسپیوں کا کام تو یہ ہے کہ آج کی حکومت کے اندرونی اور بین الاقوامی اطراف سے ہونے والے مستبدانہ اقدامات کو روکنے کے لیے جو تدبیریں ایجاد ہوئی ہیں، ان کو کچھ ترمیم کر کے یا بلاترمیم اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ایسی مساعی فساد کی تعریف میں آنے سے بچیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جہاد کی کوئی قسم قرار پائیں۔
اب مثلاً کشمیر والے کیا کرتے؟ ان کو جبری سازشی طور پر بھارت سے نتھی کیا گیا۔ اس سازش میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، نہرو، پٹیل، ریڈکلف، مہاراجا کشمیر سب شامل ہوئے۔ اس پر سخت ردعمل ہوا، کشمیری بھی اٹھ کھڑے ہوئے، مذہبی اور قواعدِ تقسیم کے رشتے سے پاکستانی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، مرنے مارنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، فوجیں بھی متحرک ہونے والی تھیں، بھارت نے قراردادِ استصواب پاس کرا کے جلتی آگ کو ٹھنڈا تو کر دیا لیکن متواتر ۵۳ سال تک اس کے نفاذ کو ٹالا گیا اور اس ملیامیٹ کرنے کے لیے نت نئے معاہدات کیے گئے۔ کشمیری مقامتی و مزاحمتی جہاد بڑھ گیا، آج جبکہ پاکستان سے جہادی قوتیں جا ملی ہیں، ان میں نظم ہے، ان کی امارت ہے، نوجوان سچے جذبے سے قربانیاں دے رہے ہیں، اس صورتحال نے بھارت کو ہلا دیا ہے۔ ادھر ہمارے علما نوجوان یہ اشغلہ لے کے میدان میں آ گئے ہیں کہ یہ تو جہاد ہی نہیں۔ جہاد کے لیے تو فلاں فلاں شرائط ضروری ہیں۔ یعنی نوجوانوں کے دل بھی توڑ دو، بھارت کو بھی تسلی دلا دو کہ ہم تمہاری گردن چھڑوا دیتے ہیں، اور امریکی کی خوشنودی بھی ہو جائے کہ جہادی رجحانات کا مٹھ مارا گیا۔
میرا ایک اور استدلال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو جان بچانے کے لیے مرے، جو مال کے لیے مرے، جو عزت کے لیے مرے، وہ شہید ہے۔ یعنی شخصی یا خاندانی سطح پر یہ ایک چھوٹا جہاد ہے۔ اس کے مطابق کسی مسلم قوم، یا شہر، یا آبادی کو بھی یہی حدیث اختیار دیتی ہے کہ وہ جانوں، مالوں، عزتوں، آزادی، حقوق، اور مظالم سے تحفظ کے لیے لڑیں اور قربان ہو کر شہید ہوں۔ یعنی یہ Standing فرمانِ رسول ہے، کسی نئے امیر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔
راشدی صاحب! میں کیا بتاؤں کہ کیا طوفان میرے اندر ہیں، مگر مجھ میں نہ کام کرنے کی طاقت ہے نہ معاونین کی ٹیم میرے پاس ہے (بلکہ ایک چپراسی بھی نہیں) گھنٹوں کے لیے بیماری دبا لیتی ہے۔ اس کے خلاف دواؤں اور دعاؤں سے جہاد کرتا ہوں۔ ہوش آتی ہے تو کچھ چیزیں پڑھتا ہوں، جن میں سے پڑھ کر کچھ پر ہنسی آتی ہے، کچھ پر رونا۔
ہزار رحمتیں مولانا مودودی کی تعلیم و تربیت پر، جو نہ تو شریعت کے دائرۂ نصوص و اجماع سے نکلنے دیتی ہے، نہ نئی نئی صورتیں احوال کی نظر انداز کر کے کنویں کا مینڈک بننے دیتی ہے۔ بغاوت سے انہوں نے سختی سے طبائع کو روک دیا، لیکن حالات نے اگر اجتہادی طرزِ فکر سے کام لینے کا مطالبہ کیا تو تفردًا نہیں بلکہ ائمہ و علما کے علوم و اخبار کی روشنی میں نئی راہیں نکالیں، اور نکال سکتے ہیں۔ یہی فرق ہے مولانا مودودیؒ اور مولانا اصلاحیؒ میں۔
نعیم صدیقی
۲ جولائی
ہمارا دینی تعلیمی نظام اور وقت کے تقاضے
ادارہ
تعلیم کی ثنویت
ہمارے ہاں تعلیم کو دو خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تعلیم ہے دینی، دوسری ہے دنیوی۔ تعلیم کی یہ ثنویت اصل میں انگریزوں کی برصغیر پر قبضے کے بعد کی پیداوار ہے جب انگریز سامراج نے مقامی تعلیم کو نظرانداز کر کے اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کے مطابق تعلیم ہمارے اوپر تھوپ دی اور مقامی تعلیم کی حوصلہ شکنی کی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مقامی لوگوں کو ان کی تہذیب، ثقافت اور کلچر سے بیگانہ کر کے ان کو ٹکے پیسے کا غلام اور نوکر بنایا جائے۔
انگریز کی سرکاری سرپرستی کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے اوپر تھوپی گئی اس تعلیم کے مقابلے میں تعلیم کا وہ قدیم نظام تھا جو مقامی مدارس و مکاتب میں پڑھایا جاتا تھا، جس کی سرپرستی خاص طور پر انگریز کے باغی، آزادی پسند ہندوستانی علماء حق کر رہے تھے، جنہوں نے انگریز کی طرف سے شروع کی گئی جدید تعلیم کی سخت مزاحمت کی۔ یہ مخالفت کسی سطحی اور جذباتی خیال کے تحت نہ تھی، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز دشمنی میں انگریزی تعلیم کی مخالفت کی۔ اصل میں وہ انگریزوں کے ایسے خطرناک وطن دشمن مقاصد کے پیش نظر کی گئی تھی جو انگریزوں نے اپنے نظام میں دانستہ طور پر شامل کیے تھے۔ چنانچہ لارڈ میکالے اور ان کی کمیٹی کی تعلیمی مقاصد اور اسکیم کی رپورٹ میں ہے کہ
’’ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہئے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔‘‘
یا بقول مسز جان کیتھر:
’’انگریزوں نے ہندوستان میں جو تعلیم یافتہ تیار کیے، وہ معمولی ایجاد اور صنعت کی استعداد بھی نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ وہ دفتروں میں کلرکوں کی خدمات سرانجام دے سکیں۔ حالانکہ سوویت روس نے ایسے تعلیم یافتہ لوگ پیدا کیے جنہوں نے نہ صرف جرمنی جیسی ترقی یافتہ اور سائنس دان قوم کو شکست دی بلکہ ان کو اپنے ملک سے بھی باہر نکال دیا۔‘‘
اس صورتحال میں ایک طرف جدید تعلیم تھی جس کا مقصد سامراجی تھا، تو دوسری طرف قدیم تعلیم تھی جو جدید ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دور میں ہندوستان کے اندر اس صورتحال پر بہت سی تحریکیں اٹھیں جن کے متعلق ہر پڑھا لکھا آدمی معلومات رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جدید ضرورتوں کو پورا کرنے کی تلاش نے انگریزی تعلیم کے شکنجے میں پھنسایا، تو بہت سوں کو قدیم ورثے کی حفاظت کے شوق اور رجعت پسندانہ ذہنیت نے ماضی کے پاتال میں گم کر دیا۔
اصل میں ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے تہذیبی، ثقافتی، علمی اور تاریخی ورثوں اور جدید دور کے تقاضوں کے امتزاج اور میلاپ سے ایک ایسا نیا تعلیمی نظام ترتیب دیا جاتا جو مقامی تہذیبی، علمی اور اخلاقی قدروں سے مالا مال ہوتا، اور جدید تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا، اور تعلیم کی دینی اور دنیوی تقسیم کی ’’بدعت‘‘ سے پاک ہوتا۔ لیکن ایسی کوششیں بہت کم ہوئیں، جو کوششیں ہوئیں وہ بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکیں۔ ایسی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ مولانا حسین احمد مدنیؒ کے آخری زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے نصاب پر نظرثانی کے لیے ایک کمیٹی بنی جس نے نصاب میں ترامیم کیں اور قدیم عقلی علوم کو نکال کر انگریزی اور جدید علوم کو ان میں شامل کرنے کی سفارشات کیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا گیا۔
بہرحال ایسی کوششوں کی ناکامی کے نتیجے میں ایک طرف قدیم تعلیم کا نظام مدارس کی شکل میں جاری رہا، تو دوسری طرف انگریزی تعلیم سرکاری سرپرستی میں جاری رہی۔ جس نے مسلم سماج کو دین دار اور بے دین، مذہبی اور لامذہبی طبقات میں تقسیم کر دیا، اور تعلیم کی دینی اور دنیوی تقسیم ہمارے سروں پر مسلط کر دی، جس کے نقصانات کی تفصیل بڑی طویل ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو قدیم نظام کو مکمل دینی نظام کہا جا سکتا ہے، اور نہ انگریزی تعلیم کو ترقی کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی تعلیم کہا جا سکتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہےکہ تعلیم کی اس ثنویت کو ختم کیا جائے۔
عربی مدارس کا فرقہ وارانہ بنیادوں پر قیام
تعلیم کی ثنویت کے بعد دوسری سب سے بڑی اور بنیادی خرابی عربی مدارس کے فرقہ وارانہ بنیادوں پر قیام کی ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی نوآبادیات سےپہلے یہاں کا سارا تعلیمی نظام غیر فرقہ وارانہ تھا، بلکہ مذہبی فرقے تو بالکل نہیں تھے۔ یہ فرقے انگریزوں کی سازش کی پیداوار ہیں۔ لیکن اس مصیبت کی جڑیں تب سے مضبوط ہوئیں جب سے تعلیمی ادارے فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم ہونے لگے۔ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تعلیمی اداروں کو غیر فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے فرقہ واریت کو ختم کرنا عین ممکن تھا، لیکن فقرہ وارانہ بنیادوں پر ہزاروں لاکھوں مدارس کا قیام اور نسل در نسل ایسے مدارس سے تیار ہو کر نکلنے والے فرقہ پرستوں کے بعد اب صدیوں تک فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوئی بھی راہ نہیں بچی ہے۔
ہر ایک فرقہ کا یہ دعوٰی ہے کہ وہ حق پر ہے اس لیے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حق کی تبلیغ کے لیے مضبوط نیٹ ورک قائم کرے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جب حق پر چلنے والا ایک فرقہ، فرقہ وارانہ بنیادوں پر مدارس کا جواز مہیا کرے گا تو اس کے مقابلے میں ۷۲، ۷۳ گروہ فرقہ وارانہ تعلیم کے ذریعے سے لاکھوں نوجوانوں کو گروہی چشمہ لگا دیں گے، اور نہ جانے کتنے مسلمان ہمیشہ کے لیے سچائی سے محروم ہو جائیں گے۔ تجربہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ فرقہ وارانہ مدارس سے فارغ ایک بھی طالب علم حق اور سچائی کو اکتسابی طور پر سوچ سمجھ کر قبول نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس جب تک کسی طالب علم کا ذہن فرقہ وارانہ تربیت نہیں پاتا تب تک اس میں سچائی کو قبول کرنے کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہےکہ مدارس کا فرقہ وارانہ بنیادوں پر قیام ایک بہت بڑی تباہ کاری ہے۔
درسِ نظامی
درسِ نظامی کا تفصیلی جائزہ اس مختصر مضمون میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ تحقیق کے بعد ہم جو کچھ سمجھ سکے ہیں اس کے مطابق حسبِ ذیل خامیاں سامنے آتی ہیں:
درسِ نظامی میں جو فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ شروع ہی سے فارسی اور عربی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، جب کہ پڑھنے والے طالب علموں کی مادری زبان نہ عربی ہے نہ فارسی۔
پھر یہ مصیبت کہ درسِ نظامی میں شامل مختلف کتابیں اتنی مختصر اور مشکل عبارات میں لکھی گئی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے پھر شرحوں کی ضرورت محسوس کی گئی، حاشیے لگانے پڑ گئے، اور پھر ان حاشیوں کے اوپر حاشیے چڑھائے گئے، اور پھر وہ سب طالب علموں کے دماغوں میں بھی بٹھانا ضروری سمجھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلبا اجنبی زبان کے اجنبی الفاظ، جملوں اور ان کی ترکیبوں میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں، اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی نہ عبارتیں حل کرنا سیکھ سکتے ہیں، نہ ان علوم میں سے ہی کچھ حاصل کر پاتے ہیں جو درسِ نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ درسِ نظامی میں شامل منطق و فلسفہ آج کے جدید منطق و فلسفہ کے زمانے میں فرسودہ ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علوم نے جتنی ترقی کی ہے اس کو نظر میں رکھا جائے۔
آج کے دور میں جو جدید فقہی مسائل ہیں، مثلاً جدید معاشیات، بینکنگ سسٹم، اور اس طرح کے دیگر مسائل، وہ بھی نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ علمِ حدیث خود علمِ حدیث کے تقاضوں کے مطابق نہیں پڑھایا جاتا۔ اصولِ حدیث، اسماء رجال، تحقیق اور تنقید کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ علمِ تفسیر میں بھی نہایت غیر ذمہ دارانہ طریقہ استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فارغ التحصیل اور دستاربند عالمِ دین ہونے کے باوجود کوئی بھی طالب علم اپنے اندر قرآن فہمی کی صلاحیت پیدا نہیں کر پاتا۔
اسی طرح درسِ نظامی کے فارغ التحصیل طلبا معاشرے کے اندر تعمیری، تخلیقی اور پیداواری عمل میں کوئی بھی حصہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس صورتحال کا تجزیہ کر کے صحت مند راہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔
طریقۂ تعلیم
مدارس میں تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں طالب علم کے سامنے مخصوص کتاب رکھی جاتی ہے۔ شاگرد کتاب کی عبارتیں حل کرتا ہے، ضمیریں اور ان کے مراجع ڈھونڈھتا ہے، یا پھر دوسری صرفی اور نحوی ترکیبیں اور قاعدے ڈھونڈھتا ہے۔ اس طرح ایک تو اصل موضوع سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور دوسرا طالب علم کو کتابوں کی عبارتیں حل کرنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس موضوع سے متعارف کرانے کے لیے کتاب پڑھائی جاتی ہے اس سے تو بالکل واقفیت نہیں ہوتی۔ جبکہ آج کل تعلیم کے بہت سے ایسے طریقے تجویز ہو چکے ہیں جن سے بہت بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
مدارس اور ان کے نصاب و طریقۂ تعلیم کے حوالے سے ہم نے اوپر جو صورت حال بیان کی ہے، اس کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کو دینی اور دنیوی خانوں میں تقسیم کیے بغیر اس کو غیر فرقہ وارانہ بنیادوں پر دینے کا بندوبست کیا جائے۔ نیز علومِ اصلیہ یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی شامل کیا جائے اور تعلیم کے جدید طریقوں کو استعمال کر کے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔
(سائنٹفک اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، حیدرآباد)
آزادیٔ کشمیر کے لیے اعلانِ جہاد کی ایک تاریخی دستاویز
ادارہ
۱۹۴۷ء میں برصغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک الگ مسلم ریاست وجود میں آئی تو غالب مسلم اکثریت کے علاقے ریاست جموں و کشمیر کے ہندو مہاراجا ہری سنگھ نے کشمیری عوام کی خواہش کے علی الرغم بھارت کے ساتھ ریاست کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ جس کے خلاف کشمیری مسلمانوں نے عَلمِ بغاوت بلند کیا اور قبائلی مسلمانوں اور پاکستانی فوج کی مدد سے مسلح جنگ لڑ کر ہری سنگھ کی فوجوں سے جموں و کشمیر کا وہ خطہ آزاد کرایا جہاں آج آزاد ریاست جموں و کشمیر کے نام سے ایک الگ حکومت قائم ہے۔
اس موقع پر جسہ پیرمنگ، راولاکوٹ، نیلا بٹ اور دیگر مقامات پر علماء کرام اور مجاہدین کے اجتماعات ہوئے جن میں مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف مسلح بغاوت کا فیصلہ کرتے ہوئے جہاد کا فیصلہ کیا گیا۔ سب سے پہلے ۲۲ جولائی ۱۹۴۷ء کو جسہ پیرمنگ میں حضرت مولانا محمد یوسف مدظلہ فاضل دیوبند، حضرت مولانا عبد العزیز تھوراڑویؒ فاضل دیوبند، اور دیگر علماء کرام نے عوام سے قرآنِ کریم پر جہاد کا حلف لیا۔ اس کے بعد ۱۵ اگست کو راولاکوٹ اور ۲۳ اگست کو نیلا بٹ میں بھی اسی قسم کے اجتماعات ہوئے۔ جبکہ ۳۰ ستمبر ۱۹۴۷ء کو موضع باسیاں (کوہالہ روڈ، مری) میں اجتماعی حلف کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اعلانِ جہاد بھی تحریر کیا گیا جو کشمیر کے بزرگ عالمِ دین اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو کے استاذ حضرت مولانا سید مظفر حسین ندوی مدظلہ نے تحریر فرمایا۔ اور اس کی بنیاد پر سردار محمد عبد القیوم خان کی قیادت میں باقاعدہ فوجی دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا گیا۔
یہ اعلانِ جہاد ہمیں حضرت مولانا سید مظفر حسین ندوی مدظلہ کے چھوٹے بھائی اور ممتاز کشمیری مؤرخ و دانشور جناب سید بشیر حسین جعفری نے مرحمت فرمایا ہے جو اُن کے شکریہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ اور اس تاریخی دستاویز کی اشاعت کے ساتھ ہم آزادکشمیر کے حالیہ انتخابات میں سردار محمد عبد القیوم خان کی قیادت میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے والی آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو نئی حکومت بنانے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے آزادیٔ کشمیر اور نفاذِ اسلام کے لیے ان کے قائد کا حلف یاد دلا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ مسلم کانفرنس کی نئی حکومت اس حلف کی صحیح طور پر پاسداری اور تکمیل کا عملی اہتمام کر سکے، آمین یا رب العالمین۔ (ادارہ)
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
آج ۳۰ ستمبر ۱۹۴۷ء کو باسیاں (کوہالہ روڈ، مری) کی مسجد میں نمازِ ظہر کے بعد ہم یہ عہد نامہ تحریر کرتے ہیں:
(۱) یہ کہ مہاراجا ریاست جموں و کشمیر ہری سنگھ نے ریاست میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بال بچے، خواتین اور مال و متاع خطرے میں ہیں، مسلمانوں کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ریاست کے مسلمانوں نے مہاراجا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس ریاست کا پاکستان سے الحاق کرے جو ایک نیا اسلامی ملک بنا ہے۔
(۲) یہ کہ ریاست کے پاکستان کو نکلنے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کوہالہ کے پل پر فوج کا پہرہ ہے، اور دریائے جہلم پر جتنی اور جہاں کشتیاں تھیں ان کو کاٹ کر بہا دیا گیا ہے، تاکہ ریاست کے مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت نہ کر سکیں، نہ ہی پاکستان کے مسلمان ہماری مدد کو ریاست میں داخل ہو سکیں۔ مہاراجا کشمیر نے اپنی ساری فوج پونچھ، میرپور، مظفرآباد میں لگا رکھی ہے، اور مشرقی پنجاب کی سکھ ریاستوں اور آر ایس ایس کی عسکری مدد بھی حاصل کی ہے تاکہ وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے تاکہ ریاست ہندو اکثریت میں بدل جائے۔
(۳) یہ کہ ان حالات میں ہم کشمیر کے اور پاکستان کے مسلمانوں پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں کافر مہاراجا کشمیر کی فوجوں کے خلاف جہاد کا آغاز کریں۔ اپنی جانوں، مال و متاع، اپنی اولاد اور اپنی عزت و آبرو، اور دین کو بچانے کے لیے میدان میں نکلیں۔
یہ پہلا مجاہدین کا دستہ جس کی تعداد انتالیس ہے، جو سردار محمد عبد القیوم کی قیادت میں ہیں، جن کو امیر المجاہدین پیر سید علی اصغر شاہ گیلانی کی برابر دینی راہنمائی حاصل ہے، اور وہ اس جہاد میں سردار محمد عبد القیوم خان کے سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہیں، ہم سب مولانا سید مظفر حسین ندوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو کے سامنے یہ عہدنامہ لکھتے ہیں کہ ان سے جہاد کی رسمی اجازت لیتے ہوئے اپنے آپ سے اور سب کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے آج نکلے ہیں۔
ہم صرف اپنے خلاف لڑنے والوں کا قتال کریں گے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ریاست پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتی۔ آزاد کردہ حصوں میں اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اسلامی نظامِ عدل اور نظامِ معیشت نافذ کریں گے۔ بیت المال کا نظام قائم کریں گے۔ اپنے امیر (کمانڈر) کا حکم تسلیم کریں گے۔ کسی جانی اور مالی قربانی کے پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔
دستخط مولانا سید مظفر حسین ندوی
دستخط سردار محمد عبد القیوم خان (بعد میں کمانڈر باغ فورسز، دو بریگیڈ)
دستخط پیر سید علی اصغر شاہ
دستخط محمد سلیم خان (بعد میں میجر، بٹالین کمانڈر)
دستخط محمد سعید خان (بعد میں میجر۔ بٹالین کمانڈر)
دستخط محمد صدیق خان (بعد میں لیفٹننٹ کرنل ۔ بٹالین کمانڈر)
علماء کرام اور دینی قائدین کی توجہ کیلئے
طارق محمود اعوان
محترم جناب ابوعمار زاہد الراشدی صاحب (جنرل سیکرٹری پاکستان شریعت کونسل)
السلام علیکم!
امید ہے آپ مع رفقائے کار بخیریت ہوں گے۔ میں کافی عرصہ سے روزنامہ اوصاف میں آپ کے کالم بعنوان ’’نوائے قلم‘‘ کا قاری ہوں۔ یہ ایک جاندار اور موقر کالم ہے جس میں حالاتِ حاضرہ اور دینی مسائل پر معلومات ہوتی ہیں۔ میں اس کو کافی پسند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ’’الہلال‘‘ میں بھی آپ کا کالم ہوتا ہے۔ الغرض جہاں آپ ایک عالم فاضل ہیں، وہاں موجودہ دور کے مسائل پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے۔ آپ کے کالم مدلل اور تاریخی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، آپ کا طرز اسلوب استدلال کا حامل ہوتا ہے۔
پچھلے ایک دو کالموں میں مجھے اس ملک کی حالت اور مستقبل کافی خطرناک نظر آ رہا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ موجودہ حکومت ایسے کام کر رہی ہے جو خطرناک نوعیت کے ہیں۔
ایک تو ٹیکسٹ بک بورڈز کا مسئلہ ہے۔ یہ بورڈز غیر ملکیوں کے حوالے کرنے کا پروگرام ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کتابیں چھاپ سکیں اور قیمتوں میں اضافہ کر کے غریبوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیں۔ غریب لوگ اور تنخواہ دار کس طرح کتابوں کی بھاری قیمت برداشت کر سکیں گے؟ صرف امیر اور جاگیردار لوگ ہی کتابوں کی قیمتیں برداشت کر سکیں گے اور تعلیم صرف ان کے بچوں کے لیے مخصوص ہو جائے گی تاکہ ان کے بچے مخصوص نصاب پڑھ کر ملکی وسائل پر قابض ہو کر ہمارے اوپر حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں اور پھر یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہر ہر چیز پر قابض ہو جائیں کیونکہ میرے خیال میں نصاب بھی ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔
اسی طرح ایک اور خطرہ کارپوریٹ فارمنگ کا ہے۔ زمین کے مالک باہر کے درآمد شدہ لوگوں کو بنانے کا منصوبہ ہے تاکہ جو فصلیں اور خوراک حاصل ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق دوسروں کو اپنی من پسند قیمتوں پر فروخت کریں۔ ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس ملک کا عام آدمی ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔
اس خطرے کی طرف اشارہ پچھلے دنوں ’’مشرق‘‘ اخبار کے کالم میں جنرل حمید گل نے کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارا ملک دوسروں کے پاس گروی رکھ دیا جائے گا۔
مولانا صاحب! یہ ملک کیا ہم نے دوسروں کا پیٹ بھرنے اور ان کو مالامال کرنے کے لیے بنایا تھا؟ غیروں کے منصوبے ہمارے ملک میں نافذ کیے جائیں گے؟ مشرکوں اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اور ہماری اولادیں تکلیف بھری زندگیاں گزاریں گے؟ مجھے بڑی تشویش ہے کہ آخر ہماری نسلوں کا کیا ہو گا؟ عام شخص کی زندگی بڑی تکلیف دہ ہو رہی ہے۔ موجودہ حکومت تو مکمل طور پر غیروں کے احکام کی منتظر رہتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ ملک صرف امیروں اور حکمرانوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ ان کی جو مرضی آئے خوشی سے کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ملک کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے۔ سارے وسائل اور سہولیات اس ملک کے بڑے بڑے افسروں اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، علاج، مکان، تعلیم سے محروم کی جا رہی ہے۔
میرے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں اور دوسرے علماء کو اکٹھا کریں کہ وہ ذاتی سوچ سے نکل کر مجموعی طور پر اس ملک کے لیے سوچیں اور فکر کریں کہ عوام کش منصوبے بنا کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ جمہوریت اور الیکشن ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اب تک اس سے کوئی فائدہ اور خیر برآمد نہیں ہوا بلکہ اس سے مزید نقصان پہنچا ہے۔ ساری دینی جماعتوں کو اکٹھا اور متحد کریں، ذاتی انا اور فائدہ کو نہ دیکھیں، اگر یہ جماعتیں اکٹھی اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئیں تو امیدِ واثق ہے کہ ملک بچ جائے گا اور عوام خوشحال ہو جائے گی۔
لادینی اور سیکولر قوتوں کو آگے نہ کریں بلکہ اسلام ہی ہمارے لیے امن و چین کا ضامن ہے جبکہ حکمران طبقہ اس بات سے ناآشنا ہے۔ اس کو اسلام سے آگہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ بہرحال آپ علماء لوگ اس ملک کی باگ ڈور جلد ہی سنبھال لیں، قبل اس کے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس ملک پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں۔
میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں، میں علماء کا قدردان ہوں اور ہر اہلِ علم و فضل کا شیدائی ہوں۔ میں خود ایم اے کرنے کے بعد ایک ہائی اسکول میں بطور معلم کام کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل میری نظروں سے ماہنامہ الشریعہ گزرا، اگر یہ اب شائع ہوتا ہے تو مجھے بھیج دیں تاکہ مزید آپ سے رابطہ استوار ہو۔ میں کوئی باقاعدہ ادیب یا لکھاری نہیں ہوں، میرے دل میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے لکھ دی ہیں، اس میں کوئی ربط نہیں ہو گا تو معاف فرمائیں، مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔
والسلام، آپ کا مخلص
طارق محمود اعوان (ایم اے) ٹانک
مری میں نفاذِ شریعت کنونشن کا انعقاد
پاکستان شریعت کونسل کی مرکزی مجلسِ شورٰی کے فیصلے
ادارہ
پاکستان شریعت کونسل نے ملک میں نفاذِ شریعت کی جدوجہد کو تیز کرنے، سودی نظام کے خاتمہ، بڑھتی ہوئی عریانی و فحاشی کی روک تھام، این جی اوز کی اسلام دشمن سرگرمیوں کے تعاقب، دستور کی اسلامی دفعات کے تحفظ، افغانستان کی طالبان حکومت کی حمایت، مجاہدینِ کشمیر کی پشت پناہی، اور خلیج عرب سے امریکی افواج کی واپسی کے لیے مشترکہ جدوجہد کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے ملک کے تمام مکاتبِ فکر کی دینی جماعتوں سے رابطے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ۹ ستمبر اتوار کو لاہور میں ’’قومی دینی کنونشن‘‘ طلب کر لیا ہے، جس میں مشترکہ جدوجہد کی عملی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا اور مختلف مکاتبِ فکر کی جماعتوں کے راہنما خطاب کریں گے۔ یہ فیصلہ پاکستان شریعت کونسل کے زیراہتمام دو روزہ ’’نفاذِ شریعت کنونشن‘‘ میں کیا گیا جو ۲۱، ۲۲ جولائی ۲۰۰۱ء کو جامع مسجد مدنی، لنگرکسی، بھوربن، مری میں کونسل کے سربراہ مولانا فداء الرحمٰن درخواستی کی زیرصدارت منعقد ہوا۔ کنونشن کی مختلف نشستوں میں مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی۔
مولانا قاضی عبد اللطیف (کلاچی)، مولانا زاہد الراشدی (گوجرانوالہ)، مولانا مطیع الرحمٰن درخواستی (خانپور)، مولانا سیف الرحمٰن درخواستی (روجھان)، مولانا عبد الرشید انصاری (کراچی)، مولانا ڈاکٹر سیف الرحمٰن ارائیں (حیدرآباد)، احمد یعقوب چودھری (راولپنڈی)، قاری محمد اکرم مدنی (سرگودھا)، مولانا معین الدین وٹو (منچن آباد)، طاہر وٹو (عارف والا)، پروفیسر حافظ منیر احمد (وزیرآباد)، پروفیسر ڈاکٹر حافظ احمد خان (اسلام آباد)، مولانا قاری محمد یوسف (ڈیرہ اسماعیل خان)، قاری جمیل الرحمٰن اختر (لاہور)، حافظ ذکاء الرحمٰن اختر (لاہور)، مخدوم منظور احمد تونسوی (لاہور)، مولانا عبد الرؤف فاروقی (لاہور)، مولانا میاں عصمت شاہ کاکاخیل (پشاور)، مولانا عبد العزیز محمدی (ڈیرہ اسماعیل خان)، مولانا محمد رمضان ثاقب (ڈیرہ اسماعیل خان)، مولانا محمد نواز بلوچ (گوجرانوالہ)، مولانا صلاح الدین فاروقی (ٹیکسلا)، حاجی جاوید ابراہیم پراچہ (کوہاٹ)، مولانا بشیر احمد شاد (چشتیاں)، مولانا حافظ مہر محمد (میانوالی)، مولانا حامد علی رحمانی (حسن ابدال)، مولانا محمد ادریس ڈیروی، (اسلام آباد)، مولانا سخی داد خوستی (ژوب)، مولانا قاری محمد نذیر فاروقی (اسلام آباد)، مولانا حافظ محمد فیاض عباسی (مری)، مولانا قاری سیف اللہ سیفی (مری)، راجہ محمد یونس طاہر ایڈووکیٹ (دھیرکوٹ)، مولانا محمد شعیب (ہری پور)، اور مولانا قاری محمد زرین عباسی (مری)۔
جبکہ کنونشن کی آخری عمومی نشست میں علاقہ کے سینکڑوں مسلمانوں اور علماء کرام نے بھی شرکت کی۔
کنونشن میں ملک کی عمومی دینی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور مختلف مقررین نے اس امر پر شدید تشویش اور اضطراب کا اظہار کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بتدریج اس کے اسلامی تشخص سے محروم کر کے ایک سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے غیر ملکی سرمایہ سے چلنے والی این جی اوز سب سے زیادہ سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں اور انہیں ان سرگرمیوں میں ریاستی اداروں کی مکمل سرپرستی اور تعاون حاصل ہے۔
کنونشن میں ایک قرارداد کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ این جی اوز کی سرگرمیوں، حسابات اور ان کے بارے میں عوامی شکایات کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور پبلک انکوائری کے ذریعے سے ایسی این جی اوز کو بے نقاب کیا جائے جو ملک کے اسلامی تشخص، قومی خودمختاری اور دینی اقدار کے خلاف کام کر رہی ہیں اور ملک میں صحیح کام کرنے والی این جی اوز کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں۔
کنونشن میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے پاکستان کی قومی تجارت پر بتدریج کنٹرول حاصل کرنے کے اقدامات اور بڑے زرعی فارموں کے نام سے زمینوں کی خریداری کی اطلاعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا اور مختلف مقررین نے کہا کہ اس طرح ملک کی تجارت اور زراعت کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے بین الاقوامی کنٹرول میں دیا جا رہا ہے اور ملک کو مکمل غلامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کنونشن میں ایک قرارداد کے ذریعے سے ملک کی تمام دینی و سیاسی جماعتوں اور محب وطن حلقوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور غلامی کے اس نئے پروگرام کو روکنے کے لیے مزاحمت کریں۔
نفاذِ شریعت کنونشن میں اس صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیا گیا کہ ملک میں دستور مکمل طور پر معطل ہے، عدالتِ عظمٰی کے جج صاحبان نے چیف ایگزیکٹو کی شخصی وفاداری کا حلف اٹھا کر ملک میں شخصی حکومت کی بنیاد رکھ دی ہے، دستور میں ہر قسم کی ترمیم کا اختیار فردِ واحد کو دے دیا گیا ہے، اور سرکاری کیمپ میں موجود این جی اوز دستور کو مکمل طور پر سیکولر حیثیت دینے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ جس سے نہ صرف وفاقِ پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں بلکہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی حیثیت اور اب تک کیے جانے والے نفاذِ اسلام کے اقدامات بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں۔
کنونشن میں مقررین نے کہا کہ قادیانی گروہ اور بین الاقوامی سیکولر لابیاں ایک عرصہ سے اس کوشش میں ہیں کہ دستورِ پاکستان میں موجود نفاذِ اسلام کی ضمانت، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی شقیں، اور تحفظِ ناموسِ رسالت کا قانون ختم کیا جائے، اور موجودہ صورتحال کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے وہ پوری طرح مستعد و متحرک ہیں، جبکہ دوسری طرف ملک کے دینی حلقے اور خاص طور پر تحفظِ ختمِ نبوت کے لیے کام کرنے والی جماعتیں اس صورتحال سے لاتعلق اور غیر متحرک نظر آ رہی ہیں جو یقیناً ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔ کنونشن میں طے کیا گیا کہ اس صورتحال کی طرف دینی جماعتوں کو توجہ دلانے کے لیے رابطے کیے جائیں گے۔
کنونشن کے مقررین نے سودی نظام کے خاتمہ میں مزید ایک سال کی توسیع کو بھی افسوسناک قرار دیا اور دینی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے عملی جدوجہد کریں۔
کنونشن میں جہادِ کشمیر کے بارے میں بعض دینی حلقوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کو مسترد کرتے ہوئے مجاہدینِ کشمیر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور ایک قرارداد کے ذریعے سے اس امر کا اعلان کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان شریعت کونسل کا موقف وہی ہے جو کشمیری عوام کا ہے کہ انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ استصواب رائے کے ذریعے سے خود کرنے کا حق دیا جائے، اور اپنے اس جائز اور مسلّمہ حق کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد شرعی جہاد کی حیثیت رکھتی ہے جس کی حمایت پاکستان کے دینی حلقوں اور عوام کی ذمہ داری ہے۔
کنونشن میں ایک قرارداد کے ذریعے سے سنی شیعہ کشیدگی کے اسباب و عوامل کی نشاندہی کے لیے اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن مقرر کرنے اور مولانا محمد اعظم طارق سمیت تمام گرفتار شدہ راہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔
کنونشن میں طے پایا کہ مولانا فداء الرحمٰن درخواستی، مولانا قاضی عبد اللطیف، اور مولانا زاہد الراشدی پر مشتمل وفد دینی جماعتوں کے راہنماؤں سے ملاقاتیں کرے گا اور ۹ ستمبر کے ’’قومی دینی کنونشن‘‘ سے قبل ۵ ستمبر کو راولپنڈی، ۶ ستمبر کو فیصل آباد، ۷ ستمبر کو چنیوٹ، اور ۸ ستمبر کو گوجرانوالہ میں علاقائی دینی کنونشن منعقد ہوں گے، ان شاء اللہ العزیز۔
مولانا سمیع الحق سے ملاقات
پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا فداء الرحمٰن درخواستی اور سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی نے گزشتہ روز اکوڑہ خٹک میں جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا سمیع الحق اور مرکزی نائب امیر مولانا قاضی عبد اللطیف سے ملاقات کی اور ان سے ملک کی عمومی صورتحال پر تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر مولانا سیف الرحمٰن ارائیں، مولانا سید محمد یوسف شاہ اور مولانا عبد الخالق آف اسلام آباد بھی موجود تھے۔ دونوں جماعتوں کے راہنماؤں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ مشترکہ دینی و قومی مقاصد کے لیے دینی جماعتوں کو مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے، اور دینی جماعتوں کو مشترکہ جدوجہد کے لیے تیار کرنے کی غرض سے دونوں جماعتوں کے راہنما مشترکہ طور پر محنت کریں گے۔
اس موقع پر پاکستان شریعت کونسل کے راہنماؤں نے چھ دینی جماعتوں کی ’’متحدہ مجلسِ عمل‘‘ کے قیام کو سراہتے ہوئے اس پر مولانا سمیع الحق کو مبارکباد پیش کی اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان شریعت کونسل کے سربراہ مولانا فداء الرحمٰن درخواستی نے مولانا سمیع الحق کو ۹ ستمبر کو لاہور میں منعقد ہونے والے ’’قومی دینی کنونشن‘‘ میں شمولیت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔
احمد یعقوب چودھری مرکزی پریس سیکرٹری ہوں گے
پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا فداء الرحمٰن درخواستی نے راولپنڈی کے جناب احمد یعقوب چودھری کو پاکستان شریعت کونسل کا مرکزی پریس سیکرٹری مقرر کیا ہے، جبکہ خانپور کے مولانا حاجی مطیع الرحمٰن درخواستی کو پاکستان شریعت کونسل صوبہ پنجاب کا نائب امیر اول، اور دھیر کوٹ آزادکشمیر کے راجہ محمد یونس طاہر ایڈووکیٹ کو مرکزی مجلسِ شورٰی کا رکن مقرر کیا ہے۔
دریں اثنا مولانا فداء الرحمٰن درخواستی نے کہا ہے کہ پاکستان شریعت کونسل ملک میں نفاذِ شریعت کے لیے راہ ہموار کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے جو اقتدار اور الیکشن کی سیاست سے الگ تھلگ رہتے ہوئے علمی و فکری بنیاد پر مصروفِ کار ہے اور کسی بھی دینی یا سیاسی جماعت کا رکن اپنی جماعت کا رکن ہوتے ہوئے بھی نفاذِ شریعت کی علمی و فکری محنت کے لیے پاکستان شریعت کونسل میں شامل ہو سکتا ہے۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’احکام القرآن‘‘ اور ’’احکام الاسلام‘‘
دارالعلوم عربیہ ایبٹ
آباد کے بانی حضرت مولانا محمد ایوب ہاشمیؒ (فاضل دیوبند) ہزارہ کے بزرگ
علماء میں سے تھے جنہوں نے ایک عرصہ تک اس خطے میں دینی علوم کی ترویج و
اشاعت اور عوام کے عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی اصلاح کے لیے
مخلصانہ جدوجہد کی ہے اور تقریر و تدریس کے علاوہ تحریر کے میدان میں
نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں۔ مختلف موضوعات پر ان کی نصف درجن سے زائد
معلوماتی اور اصلاحی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں سے دو اس وقت ہمارے
سامنے ہیں:
ایک ’’احکام القرآن‘‘ کے نام سے ہے جس میں قرآن کریم کے
مختلف مضامین کی آسان زبان میں وضاحت کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کے بارے میں
بہت سی مفید معلومات یکجا کر دی گئی ہیں۔ ۱۹۰ صفحات کی اس مجلد کتاب پر
قیمت درج نہیں ہے۔
دوسری کتاب ’’احکام الاسلام‘‘ ہے جس میں روز مرہ
پیش آنے والے دینی مسائل، ایمانیات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وراثت
وغیرہ سے متعلق اسلامی احکام عام فہم انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس مجلد
کتاب کے صفحات ۱۵۸ ہیں۔
یہ دونوں کتابیں درج ذیل ایڈریس سے طلب کی جا سکتی ہیں:
مولانا قاری عتیق الرحمٰن ہاشمی، دارالعلوم عربیہ سراج العلوم، مدنی مسجد، مری روڈ، دھتوڑ، ایبٹ آباد
’’قبر ۔ ایک شدید غلط فہمی کا ازالہ‘‘
جامعہ
اسلامیہ راولپنڈی صدر کے دارالافتاء کے سربراہ مولانا مفتی محمد اسماعیل
طورو نے عذابِ قبر کے بارے میں ایک فتوٰی جاری کیا کہ عذابِ قبر کا منکر
مسلمان نہیں ہے، جو مختلف دینی و علمی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا اور اس
پر ملک کے متعدد اداروں اور شخصیات کی طرف سے اظہارِ خیال کیا گیا۔
مفتی
صاحب نے اس ساری بحث کو یکجا کر کے اہلِ سنت کے اس موقف کی وضاحت کی ہے کہ
مطلقاً عذابِ قبر کا انکار کفر ہے اور نفسِ عذابِ قبر کو تسلیم کرتے ہوئے
اس کی کیفیات اور تعبیرات میں اختلاف کے مختلف مدارج ہیں، جن میں ایک یہ ہے
کہ اہلِ سنت کی اجماعی تعبیر و تشریح سے ہٹ کر عذابِ قبر کی الگ تعبیر
کرنا گمراہی ہے۔
۱۱۶ صفحات کے اس کتابچہ پر قیمت درج نہیں ہے اور اسے جامعہ اسلامیہ، کشمیر روڈ، راولپنڈی صدر سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
ماہنامہ ’’آبِ حیات‘‘ لاہور
مولانا
محمود الرشید حدوٹی کا تعلق جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے اور دینی حلقوں میں
ایک معروف صاحبِ قلم کے طور پر متعارف ہیں۔ مختلف اخبارات و جرائد میں ان
کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں جو ان کے مخصوص تحقیقی ذوق کا آئینہ دار ہیں۔
اب انہوں نے ماہنامہ ’’آبِ حیات‘‘ کے نام سے ایک ماہوار جریدہ کا آغاز کیا
ہے جو دینی صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ اس وقت جولائی ۲۰۰۱ء کا شمارہ
ہمارے سامنے ہے جو معلوماتی اور تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہے۔
۴۸ صفحات کے اس رسالہ کی قیمت ۱۰ روپے جبکہ سالانہ زرخریداری ۱۰۰ روپے ہے۔ خط و کتابت کا پتہ یہ ہے:
مولانا محمود الرشید حدوٹی، جامعہ اشرفیہ، مسلم ٹاؤن، فیروز پور روڈ، لاہور
سہ ماہی ’’ایقاظ‘‘ لاہور
لاہور
سے شائع ہونے والے نئے سہ ماہی مجلہ ’’ایقاظ‘‘ کی پہلی جلد کے تین شمارے
۲، ۳، ۴ اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مجلہ جناب حامد محمود کی زیرادارت شائع
ہو رہا ہے اور اس کے مضامین کا زیادہ حصہ مجلہ کے نام کی مناسبت سے فکری و
علمی موضوعات پر بیداری کے رجحانات کا آئینہ دار ہے۔
عالمِ اسلام
میں دینی بیداری کا فروغ، استعماری غلبہ سے نجات، استعمار کے آلہ کار
حکمران طبقوں سے گلوخلاصی، اور عصرِ حاضر کی ضروریات کے مطابق اسلامی عقائد
کی تعبیر و تشریح ہر اس فکری و علمی حلقہ کے بنیادی موضوعات ہیں جو اس
میدان میں مصروفِ کار ہے۔
اور ’’ایقاظ‘‘ کا فکری و علمی دائرۂ کار
بھی ان شماروں سے یہی محسوس ہو رہا ہے جس پر عرب ممالک کی اس سلفی تحریک کی
چھاپ نمایاں نظر آ رہی ہے جو مختلف ممالک میں مذکورہ بالا مقاصد کےلیے
اپنے مخصوص ذوق کے تحت کام کر رہی ہے۔
عقائد کی تعبیر و تشریح میں
نقطۂ نظر کا اختلاف ایک طبعی امر ہے اور اگر اسے باہمی برداشت اور احترام
کے ماحول میں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھایا
جائے تو نظریات و افکار کا یہ تنوع امت کے لیے باعثِ رحمت بھی ہے۔ اس لیے
ہم اس توقع کے ساتھ دینی صحافت میں اس نئے فکری جریدہ کا خیرمقدم کرتے ہیں
کہ یہ جریدہ مذکورہ بالا موضوعات و عنوانات کے حوالے سے بحث و مباحثہ کو
علمی انداز میں مثبت طور پر آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔
۸۰ کے لگ
بھگ صفحات پر مشتمل اس جریدہ کی قیمت ۲۰ روپے اور سالانہ زرخریداری ۸۰ روپے
ہے ۔ اور رابطہ کے لیے پوسٹ بکس ۱۷۱۱ لاہور ک ےپتہ پر خط و کتابت کی جا
سکتی ہے۔
’’غیر مقلدین کے متضاد فتوے‘‘
ائمہ اربعہ رحمہم
اللہ تعالیٰ کے مقلدین پر غیر مقلدین کی طرف سے اکثر اعتراض کیاجاتا ہے کہ
ان کے مسائل اور فتووں میں تضاد ہے۔ حالانکہ مسائل و احکام میں فقہی اختلاف
ایک طبعی اور فطری امر ہے۔ مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے استاذِ حدیث
مولانا عبد القدوس خان قارن نے اس کتابچہ میں غیر مقلد علماء کے مسائل اور
فتاوٰی کے باہمی تضاد کو بے نقاب کیا ہے اور باحوالہ نشاندہی کی ہے کہ
مقلدین پر اختلاف کا الزام لگانے والوں کے باہمی اختلافات کی حالت کیا ہے۔
صفحات ۱۰۰ ، قیمت ۲۷ روپے، ملنے کاپتہ، عمر اکادمی: نزد گھنٹہ گھر،
گوجرانوالہ۔
’’فری میسنری ۔ اسلام دشمن خفیہ یہودی تنظیم‘‘
معروف
دانشور جناب بشیر احمد نے، جن کی تصانیف (۱) بہائیت (۲) احمدیہ موومنٹ (۳)
قادیان سے اسرائیل تک، شائع ہو کر اہلِ علم سے دادِ تحقیق وصول کر چکی
ہیں، فری میسنری تحریک اور اس کی سرگرمیوں پر قلم اٹھایا ہے اور ساڑھے تین
سو صفحات کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل زیرنظر کتاب میں فری میسنری کے آغاز،
طریق کار، مختلف ممالک میں اس کی سرگرمیوں، اور خاص طور پر خلافتِ عثمانیہ
کے خاتمہ اور اسرائیل کے قیام میں اس کے کردار کو بے نقاب کیا ہے۔
اس کتاب کی قیمت دو سو روپے ہے اور اسلامک اسٹڈی فورم، پوسٹ بکس ۶۳۹ راولپنڈی سے طلب کی جا سکتی ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو قائد اعظمؒ کی ہدایت
ادارہ
۱۵ جولائی ۱۹۴۸ء کو کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر بانئ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے اپنے خطاب میں فرمایا:
’’میں اشتیاق اور دلچسپی سے معلوم کرتا رہوں گا کہ آپ کی ’’مجلسِ تحقیق‘‘ بینکاری کے ایسے طریقے کیونکر وضع کرتی ہے جو معاشرتی اور اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات کے مطابق ہوں۔
مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لاینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں اور اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ مغرب کو اس تباہی سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ مغربی نظام افرادِ انسانی کے مابین انصاف کرنے اور بین الاقوامی میدان میں آویزش اور چپقلش دور کرنے میں ناکام رہا ہے، بلکہ گزشتہ نصف صدی میں ہونے والی دو عظیم جنگوں کی ذمہ داری سراسر مغرب پر عائد ہوتی ہے۔ مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور مشینوں کی دولت کے زبردست فوائد رکھنے کے باوجود انسانی تاریخ کے بدترین باطنی بحران میں مبتلا ہے۔
اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو عوام کی پرسکون خوشحالی حاصل کرنے کے اپنے نصب العین میں ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اپنی تقدیر ہمیں منفرد انداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔
ایسا نظام پیش کر کے گویا ہم مسلمان کی حیثیت میں اپنا فرض سرانجام دیں گے۔ انسانیت کو سچے اور صحیح امن کا پیغام دیں گے۔ صرف ایسا امن ہی انسانیت کو جنگ کی ہولناکی سے بچا سکتا ہے، اور صرف ایسا امن ہی بنی نوع انسان کی خوشی اور خوشحالی کا امین ہو سکتا ہے۔‘‘
بحوالہ ’’نظریہ پاکستان اور اسلامی نظام‘‘
مطبوعہ مکتبہ محمود، مکان نمبر ۱ رسول پور اسٹریٹ، اچھرہ، لاہور
دین کی دعوت و اقامت کا فریضہ
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت اقامتِ دین کی ہے۔ آج دنیا کی پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب مخلوق ایمان کی پیاسی ہے مگر ان تک ایمان پہنچانے والا کوئی نہیں۔ نہ کوئی مال خرچ کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے۔ اگر مسلمان کے مال و دولت کا رخ ایمان کے متلاشیوں کی آبیاری کی طرف ہو جائے تو یہ مال کا بڑا اعلیٰ مصرف ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ مال ذاتی عیش و عشرت اور رسومِ باطلہ کے فروغ کے لیے تو نہیں دیا بلکہ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے عنایت کیا ہے۔ غیر مسلم اقوام میں تبلیغِ دین کی سخت ضرورت ہے جس کے لیے مال اور وقت درکار ہے۔ تبلیغی جماعت والے جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو کُل ضرورت کا ایک فیصد بھی نہیں، اگرچہ یہ بھی غنیمت ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ باقی ۹۹ فیصد کام کون کرے گا؟ آپ ذرا حساب لگا کر دیکھیں کہ کُل دولت کا کتنے فیصد اقامتِ دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ جواب صفر آئے گا۔
یہ دین تو بالکل برحق ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قائم بھی رکھے گا، مگر ہم اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہے ہیں؟ کچھ غریب غرباء لوگ اور علماء حق ہر دور میں موجود رہے ہیں جو حتی الامکان کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر اس معاملہ میں اجتماعیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔
پوری دنیا کے مسلمان روبہ زوال ہیں اور ذلت کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مسلمان حکمران بھی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں یا جنگ و جدال میں مصروف ہیں۔ دین کی تقویت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جاہ و مال دونوں چیزیں عطا فرمائیں، ذرا بتاؤ تو سہی ان کو دین کے لیے کس حد تک استعمال کیا جا رہا ہے؟
ستمبر ۲۰۰۱ء
’’دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا‘‘
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
ملٹی نیشنل کمپنیاں جس طرح پاکستان میں تجارت، صنعت اور زراعت کے شعبہ میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ملکی معیشت بتدریج ان کے قبضے میں جا رہی ہے، اس سے ہر باشعور شہری پریشان ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر قسم کی پریشانی اور اضطراب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو آگے بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے کا گرین سگنل دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت اور محصولات کے نظام میں شرکت کے ذریعہ کنٹرول حاصل کیا تھا اور فلسطین میں یہودیوں نے زمینوں کی وسیع پیمانے پر خریداری کے ذریعے سے قبضے کی راہ ہموار کی تھی۔ اس پس منظر میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ایک طرف پاکستان کی صنعت و تجارت پر کنٹرول حاصل کر کے قومی معیشت کو بین القوامیت کے جال میں مکمل طور پر جکڑنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں اور دوسری طرف ’’کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ‘‘ کے نام پر پاکستان کی زمینوں کی وسیع پیمانے پر خریداری کر کے اس ملک کے باشندوں کو اپنی زمینوں کی ملکیت کے حق سے بھی محروم کر دینا چاہتی ہیں۔
ہم ایک عرصہ سے بین الاقوامی رپورٹوں میں پاکستان کے اندر ’’مسیحی ریاست‘‘ کے قیام کے پروگرام کا تذکرہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی عملی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی البتہ اب فلسطین کے تجربہ کو سامنے رکھتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے پاکستانی زمینوں کی وسیع پیمانے پر خریداری کا منصوبہ پڑھ کر ’’مسیحی ریاست‘‘ کے قیام کا طریق واردات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اس سلسلے میں روزنامہ اوصاف اسلام آباد کی ۲۸ اگست ۲۰۰۱ء کو شائع کردہ ایک خبر ملاحظہ فرمائیے اور اگر آپ اس خوفناک سازش کی روک تھام کے لیے کسی درجے میں کچھ کر سکتے ہوں تو خدا کے لیے اس میں کوتاہی سے کام نہ لیجئے۔
فیڈرل لینڈ کمیشن نے کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے تحت ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لامحدود سرکاری زمین فروخت کرنے کی حکومتی پالیسی کو آئین کے متصادم اور اسلامی احکامات اور سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بنچ کے ایک فیصلے کے منافی قرار دیا ہے جبکہ سنٹرل بورڈ آف ریونیو (سی بی آر) نے کارپوریٹ فارمنگ کرنے والی سرمایہ کار کمپنیوں کو ٹیکس میں رعایت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لامحدود زمین فراہم کرنے کے حوالے سے پالیسی کو حتمی شکل نہ دینے کے باوجود سرمایہ کاری بورڈ نے کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے تحت کثیر القومی کمپنیوں کو آئین اور اسلامی احکامات کے منافی لا محدود سرکاری زمین خریدنے کی ایک کتابچے کے ذریعے پیش کش کی ہے۔
ذرائع کے مطابق اس ضمن میں وفاقی وزارت زراعت نے آئین میں ترمیم کی سفارش کی ہے جس کے لیے زراعت کی وزارت کی جانب سے کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے تیار کردہ سفارشات کی منظوری چیف ایگزیکٹو ۱۳ مارچ ۲۰۰۱ء کو دے چکے ہیں تاہم لا محدود زمین فراہم کرنے کی پیش کش کا معاملہ آئین اور اسلامی احکامات کے منافی ہونے کے باعث حل نہیں ہو سکا ہے۔ آئین کے ایم ایل آر ۱۱۵ کے سیکشن ۷ اور ایم ایل آر ۶۴ کے سیکشن ۸ میں ترمیم کے متعلق سمری چیف ایگزیکٹو سیکرٹریٹ کو بھجوا دی گئی ہے جبکہ وفاقی وزارت قانون و انصاف کو معاملے پر رائے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ سنٹرل بورڈ آف ریونیو کا اس ضمن میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ٹیکس رعایت دینے کے معاملے پر رائے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ سنٹرل بورڈ آف ریونیو کا اس ضمن میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ٹیکس رعایت دینے کے معاملے پر موقف ہے کہ کارپوریٹ کمپنیوں سے ۴۵ فیصد تک انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے لہذا کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ کے تحت سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیاں بھی اتنی ہی شرح سے انکم ٹیکس ادا کریں گی۔سی بی آر کا مزید موقف ہے کہ سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے پرانی مشینری کی درآمد پر ٹیکسوں میں رعایت نہیں دی جا سکتی البتہ نئی مشینری کی درآمد پر رعایت دی جا سکتی ہے۔
وزارت زراعت نے سفارش کی تھی کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پرانی مشینری پر ٹیکس میں رعایت دی جائے اور بارانی علاقوں میں کارپورییٹ فارمنگ کی ابتدا کرنے والی کمپنیوں کو ۷ سال، نہری علاقوں میں فارمنگ کرنے والی کمپنیوں کو ۵ سال اور قابل کاشت ضائع شدہ زمین پر فارمنگ کرنے والی کمپنیوں کو ۱۰ سال کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے۔ ان تمام سفارشات پر وفاقی سیکرٹری خزانہ معین افضل کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی نے اس ضمن میں اپنی سفارشات کو حتمی شکل نہیں دی ہے لیکن سرمایہ کاری بورڈ نے جاری کردہ کتابچے میں ٹیکسوں میں چھوٹ کے لیے ترغیبات کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کتابچے دنیا بھر میں موجودہ پاکستانی سفارت خانوں کو ارسال کر دیے گئے ہیں جس کی بنا پر پاکستانی سفارت خانوں میں کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ میں سرمایہ کرنے کے لیے درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن پالیسی کی حتمی منظوری ابھی تک زیر غور ہے۔
غیر مستوجب حد جرائم میں مجرم کو تعزیری سزا (۳)
قاضی محمد رویس خان ایوبی
غیر مستوجب حد جرائم پر تعزیری سزاؤں کے نظائر
(۱) حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور وہ ایک اجنبیہ کے ساتھ ایک ہی بستر میں لیٹا ہوا پکڑا گیا تھا، تاہم اس کے خلاف بدکاری کی شہادتِ شرعیہ نہ پیش کی جا سکی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اس شخص کو چالیس کوڑوں کی سزا دی نیز اسے مجمع عام کے سامنے زجر و توبیخ بھی کی۔ اس پر قبیلہ قریش کے چند معززین کا ایک وفد حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے خلاف حضرت عمرؓ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ہمارے قبیلے کے ایک معزز شخص کو سربازار رسوا کر دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے عبد اللہ بن مسعودؓ کو طلب فرما کر واقعہ سے متعلق استفسار کیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا، ہاں، اس کے خلاف لوگوں نے دعوٰی کیا کہ وہ ایک اجنبیہ کے لحاف میں گھسا ہوا تھا، لحاف میں گھس کر لیٹنے کے سوا اور کوئی گواہ اس کی بدکاری پر نہیں پیش کیا گیا لہٰذا میں نے اسے تعزیرًا چالیس کوڑے مارے اور لوگوں میں اس کی تشہیر کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، آپ کے خیال میں اسے یہی سزا دینی چاہیے تھی؟ ابن مسعودؓ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ (۳۴)
اس حدیث سے جو فقہی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ حسبِ ذیل ہیں:
۱۔ اجنبیہ کے ساتھ لیٹنا قابلِ تعزیر جرم ہے۔ اسی طرح اجنبیہ کو بہلا پھسلا کر اور سبز باغ دکھا کر بھگا لے جانا، نیز ہر وہ طریقہ جس میں اجنبیہ کے ساتھ خلوت اور فحاشی کا ارتکاب پایا جائے، اگرچہ زنا کا فعل وقوع پذیر نہ ہو، سب اعمالِ معصیت ہیں اور ہر معصیت قابلِ تعزیر جرم ہے جبکہ وہ ’’حد‘‘ تک نہ پہنچی ہو۔
۲۔ اگر قاضی یہ سمجھتا ہے کہ مجرم کے لیے بدنی سزا کافی نہیں تو اسے زجر و توبیخ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی سزائے تعزیر کا حصہ ہے۔
۳۔ اگر جج کے فیصلے سے کوئی فریق ناراض ہو تو مجاز اتھارٹی سے شکایت کرنا توہینِ عدالت نہیں۔
۴۔ تعزیری سزا میں یہ جج کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنی سزا دیتا ہے۔ تاہم حکومت کو اس ضمن میں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ سزا کی تعیین کا اختیار حاصل ہے۔
سو ایسے تمام جرائم میں جو اس طرح سرزد ہوں، ان میں اگرچہ حد نافذ نہیں ہو گی لیکن سزائے تعزیر واجب ہو گی تاکہ فحاشی کا قلع قمع کیا جا سکے۔ حدود کی سزا نہ صرف بہت کم جرائم میں مقرر ہے بلکہ اس کے اثبات کے لیے نہایت مشکل اور نادر الوجود وسائل درکار ہیں۔ اس لیے شریعت نے باب التعزیر کھلا رکھا ہے تاکہ مجرموں کو شبہات کی چھتری تلے جرائم کے بے دریغ ارتکاب سے روکا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سزائے تعزیر کے اثبات کے لیے اثباتِ حدود سے کم درجے کے وسائل رکھے گئے ہیں تاکہ مجرم بچ کر نہ جا سکے۔ اگر زنا، سرقہ، منشیات کے استعمال، ارتداد اور تہمت کی ایسی صورتوں میں جو غیر مستوجب حد ہوں، مجرم کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا جائے تو غور فرمائیے کہ کسی عفیفہ کی عزت اوباشوں کے ہاتھوں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ کسی شخص کا مال چوروں سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ منشیات سے کسی معاشرے کو کیونکر پاک رکھا جا سکتا ہے؟ کسی گمراہ کو عقائدِ فاسدہ کے پھیلانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟
(۲) حضرت عمرؓ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک شخص خون آلود تلوار لیے دربار میں حاضر ہوا، لوگوں کا ہجوم اس کے پیچھے پیچھے تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ شخص قاتل ہے، اس نے ہمارے آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے قاتل سے استفسار فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنی بیوی کی برہنہ رانوں کے درمیان تلوار کا وار کیا ہے۔ اگر اس کی رانوں کے درمیان کوئی تھا تو میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ فاروقِ اعظمؓ نے قاتل سے تلوار لے کر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے فرمایا ان عاد فعد ’’اگر پھر ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو ایسے ہی کرو جیسے اب کیا ہے‘‘ (۳۵)۔
اس روایت سے فقہاء اسلام نے یہ قانونی استنباط کیا ہے کہ:
۱۔ اگر کوئی شخص حالتِ تلویث بالجریمہ میں مندرجہ بالا صورتحال سے دوچار ہو تو وہ مجرم کو قتل کر سکتا ہے، ایسے قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، البتہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے اسے مناسب سزا دی جا سکتی ہے۔ بشرطیکہ مجرم کو دھمکی سے، یا ہوائی فائرنگ سے، یا شور مچا کر روکا جا سکتا ہو۔ اور اگر ایسا کرنے کے باوجود مجرم باز نہ آئے تو قاتل پر تعزیر بھی نہیں ہے، اور وہ جب بھی اس طرح کے مجرم کو اس حالت میں پائے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ تمام امور مقدمہ کے تفصیلی حالات سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جج کو نہایت دقتِ نظر سے فیصلہ کرنا ہو گا تاکہ لوگ اس طرح کی روایات کو آڑ بنا کر بیویوں کے قتل کا مشغلہ نہ اپنا لیں۔
۲۔ مجمع میں سے کسی آدمی نے مقتول کے، قاتل کی بیوی کی رانوں میں موجودگی کی تردید نہیں کی۔ ان کا یہ سکوت مقتول کے ملوث بالجریمہ ہونے کا قرینہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے ہجوم کے سکوت کی وجہ سے مزید کوئی شہادت طلب نہیں کی۔ یہ قتل تعزیرًا ہے، حد نہیں۔
(۳) عبد الرزاق حسن روایت کرتے ہیں کہ:
ان رجلا وجد مع امراۃ رجلا قد اغلق علیھا الباب وارحی علیھا الاستار فجلدھا عمر مائۃ جلدۃ۔
’’ایک شخص نے دیکھا کہ ایک مرد اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ موجود ہے، دروازہ بند ہے اور پردے گرے ہوئے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے دونوں کو سو کوڑے لگائے۔‘‘(۳۶)
اس روایت سے حسبِ ذیل باتیں مستنبط ہوتی ہیں:
۱۔ یہ فحاشی غیر موجب حد تھی۔ اجنبیہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، دروازے بند کرنا اور پردے گرانا قابلِ تعزیر جرم ہے۔ گو یہاں صریح زنا کے ارتکاب کا کوئی ثبوت نہیں لیکن سقوطِ حد کی وجہ سے اس شخص کو بری نہیں کیا گیا بلکہ خلوت اختیار کرنے کی بنا پر دونوں کو کوڑے مارے گئے۔
۲۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر داخل ہونے والا شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور دربارِ عمرؓ میں پیش ہونے کے بعد اس نے گھر میں داخل ہونے اور پردے گرانے کے اقدام سے انکار نہیں کیا۔ یہاں بھی اس کے سکوت کو تعزیر کے نفاذ کے لیے اقرار کے قائم مقام قرار دیا گیا، جبکہ حد میں سکوتِ مجرم سے اقرار ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چار مرتبہ اقرار نہ کرے۔
عادی مجرم اور تعزیری سزا
کان عثمان یری الجمع بین الحد والتعزیر اذا کان ما یوجب ھذا الجمع وقد فعل ذالک فی من ادمن علی شرب الخمر فضربہ الربعین سوطا حدا و اربعین تعزیرا الاصرارہ علی شرب الخمر بینھما ھو لم یضرب الذی ولہ فشرب غیر اربعین سوطا۔
’’حضرت عثمانؓ کے خیال میں حد اور تعزیر دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے جبکہ ایسا کرنا ضروری ہو۔ آپ نے ایک عادی شراب نوش کو چالیس کوڑے بطور حد سزا دی اور چالیس بطور تعزیر کیونکہ وہ عادی شراب نوش تھا۔ جبکہ اگر کوئی شخص محض ’’زلت‘‘ کی بنیاد پر ایک آدھ دفعہ شراب نوشی کا ارتکاب کر لیتا تو اسے حضرت عثمانؓ صرف چالیس کوڑوں کی سزا دیتے۔‘‘ (۳۷)
اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمانؓ کے نزدیک شراب نوشی کی سزا صرف چالیس کوڑے ہے اس لیے انہوں نے عادی مجرم کو چالیس کوڑے بطور حد لگائے اور چالیس کوڑے بطور تعزیر۔ یہ حضرت عثمانؓ کا فقہی اجتہاد ہے۔
شربِ خمر کی حد میں فقہاء کا اختلاف حسبِ ذیل ہے: احناف اور مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ شربِ خمر کی حد ۸۰ کوڑے ہے، سفیان ثوریؒ بھی اسی کے قائل ہیں کیونکہ اس مقدار پر صحابہؓ کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ امام شافعیؒ کا موقف یہ ہے کہ حد ۴۰ کوڑے ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔(۳۸)
سزائے تعزیر کا ثبوت
حدود کا ثبوت تو قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے ملتا ہے۔ اور وہ سزا ایسی سزا ہے جس کی مقدار خداوندِ قدوس اور رسول کریم ﷺ نے متعین فرما دی ہے۔ تعزیری سزاؤں کی مقدار کی تعیین قرآن و حدیث میں موجود نہیں بلکہ یہ امر حکومتِ وقت کے سپرد کیا گیا ہے کہ جیسے مناسب سمجھے اور جن جرائم کو مناسب سمجھے انہیں تعزیری جرم قرار دے، بشرطیکہ شریعت کے حلال کردہ کاموں کو حرام اور حرام کو حلال قرار نہ دیا گیا ہو۔ باقی امور میں اسلامی ریاست کے مسلمان حکمرانوں کو تعزیرات میں وسیع اختیارات حاصل ہیں جبکہ ریاست کے دیگر معاملات میں بھی عدل و انصاف اور انسانی حقوق اور مساوات کا بندوبست حتی الامکان کر لیا گیا ہو۔ کیونکہ سزاؤں کا اختیار بھی، چاہے وہ حدود ہوں یا تعزیرات، صرف اس حکومت کو حاصل ہے جو رعیت کے لیے روزگار، تعلیم، علاج، چھت مہیا کرنے کی ذمہ داری نبھائے۔ صرف مارنا پیٹنا، جیلوں میں بند کرنا، پھانسی کے تختے پر لٹکانا اسلامی ریاست کے فرائض کا حصہ نہیں۔ بلکہ عوام کے لیے ہر طرح کی فلاح و بہبود کا بندوبست اور ہر طرح کے استحصال کا قلع قمع کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
جو حکومت لوگوں سے زکوٰۃ اور ٹیکس وصول کرنے کا حق مانگتی ہے اس کے منصبی فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جرائم کے اسباب پر غور کرے اور ان اسباب کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا حکومت کا فرض ہے۔ اطاعت اسی صورت میں ہو گی جبکہ اولی الامر مطیع کے حقوق کی ذمہ داری نبھائیں۔ صرف سزاؤں کے نفاذ سے کوئی حکومت اسلامی حکومت نہیں کہلا سکتی، ایسی حکومت مسلمانوں کی حکومت تو ہو سکتی ہے، اسلامی نہیں۔
ثبوتِ تعزیر
قرآن کریم میں ارشاد ہے:
واللاتی تخافون نشوزھن فعظوھن واھجروھن فی المضاجع واضربوھن۔
’’اور جو عورتیں نافرمانی اختیار کریں، انہیں نصیحت کرو، ان کے بستر الگ کرو اور انہیں جسمانی سزا دو۔‘‘
یعنی اگر کوئی عورت خاوند کے ساتھ بدمزاجی سے پیش آئے اور نافرمانی کرے، اس کو راہِ راست پر لانے کے تین درجے ہیں: (۱) زبانی فہمائش (۲) ازدواجی تعلقات کا خاتمہ (۳) جسمانی سزا۔
زجر و توبیخ، ازدواجی تعلقات کا خاتمہ یہ سب تعزیری سزائیں ہیں۔ اور اگر ان دو سزاؤں سے باز نہ آئے تو پھر جسمانی سزا دی جائے گی جس سے نہ تو جسم پر کوئی نشان پڑے اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ سزائیں تادیباً ہیں، حدًا نہیں۔ ہر جرم پر تادیبی سزا دی جا سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم نے خاوند کو تادیباً بیوی کو سزا دینے کا اختیار دیا ہے تو حاکمِ مملکت کو بدرجہ اولٰی یہ حق حاصل ہے کہ وہ رعیت کے ان لوگوں کو تعزیری سزائیں دے جو قانون شکنی کے مرتکب ہوں۔(۴۰)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس لیے سزا دی کہ اس نے دوسرے کو مخنث (ہیجڑا) کہہ دیا تھا۔ ایک شخص کو آپ نے قید بھی فرمایا۔(۴۱)
فقہاء اسلام کی آرا
التعزیر عقوبۃ تجب حقا للہ تعالیٰ او لآدمی فی کل معصیۃ لیس فیھا حد ولا کفارۃ۔
’’تعزیر ایسی سزا ہے جو کسی ایسے جرم میں دی جائے گی کہ حق اللہ یا حق العبد سے تعلق رکھتا ہو، مگر نہ تو اس میں حد مقرر ہو اور نہ کفارہ۔(۴۲)
علامہ ابن عابدینؒ فرماتے ہیں:
ھو تادیب دون الحد۔
’’حد سے کم سزا کو تعزیر کہتے ہیں۔‘‘ (۴۳)
ڈاکٹر صبحی محمصانیؒ فرماتے ہیں:
وھو العقوبۃ التی یفرضھا القاضی علی جنایۃ او معصیۃ لیس لھا حد شرعی ای لیس فیھا عقوبۃ مقدرۃ شرعا۔
’’تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قاضی ہر اس جرم یا گناہ میں جزا کے طور پر نافذ کرے جس میں شرعی طور پر کوئی متعین سزا نہ ہو۔‘‘(۴۴)
احناف کے مشہور محقق علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں:
اما سبب وجوبہ فارتکاب جنایۃ لیس فیھا حد مقرر فی الشرع سواء اکالت الجنایۃ علی حق اللہ کترک الصلوۃ والصوم۔
’’تعزیر کے وجوب کا سبب کسی ایسے جرم کا ارتکاب ہے جس کی سزا شریعت میں متعین نہ ہو۔ یہ جرم حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ہو یا کسی اور جرم کا ارتکاب، جیسے نماز یا روزہ کا ترک کرنا۔‘‘
امام مجد الدین ابی البرکاتؒ ’’المحرر فی الفقہ‘‘ میں فرماتے ہیں:
وھو واجب فی کل معصیۃ لاحد فیھا ولا کفارۃ کاستمتاع لاحد فیہ۔
’’تعزیر ہر اس معصیت میں واجب ہے جس میں نہ حد ہو اور نہ کفارہ۔ مثلاً عورت سے ایسا جنسی تلذذ حاصل کرنا جس پر حد نافذ نہ ہوتی ہو۔‘‘(۴۶)
حنابلہ کے متبحر محقق اور امام علامہ ابن قدامہؒ فرماتے ہیں:
وھو التادیب وھو واجب فی کل معصیۃ لاحد فیھا ولا کفارۃ کالاستمتاع الذی لا یوجب الحد واتیان المراۃ المراۃ سرقۃ ما لا یوجب القطع۔
’’تعزیر تادیب کو کہتے ہیں جو ہر ایسے جرم میں واجب ہے جس میں کفارہ یا حد نہ ہو جیسے ایسا جنسی تلذذ جس میں حد نہ ہو اور عورت کا عورت سے استلذاذ اور ایسی چوری جس میں قطع ید نہ ہو۔‘‘(۴۷)
موسوعۃ فقہ عبد اللہ بن مسعودؓ میں تحریر ہے:
التعزیر ھو العقوبۃ المفروضۃ علی جریمۃ لم یات الشارع بعقوبۃ محددۃ لھا۔
’’تعزیر وہ سزا ہے جو کسی ایسے جرم پر نافذ کی جائے جس پر شریعت میں کوئی متعین سزا بیان نہ کی گئی ہو۔‘‘(۴۸)
الشیخ الامام السید السابق مصریؒ رئیس قسم القضاء ام القرٰی یونیورسٹی مکہ مکرمہ اپنی شہرۂ آفاق تصنیف فقہ السنۃ میں فرماتے ہیں:
التادیب علی ذنب لاحد فیہ ولا کفارۃ ای انھا عقوبۃ تادیبۃ یفرضھا الحاکم علی جنایۃ او معصیۃ۔
’’تعزیر ایسی تادیب کو کہتے ہیں جو کسی ایسے جرم یا گناہ میں بطور سزا دی جائے جس میں حد یا کفارہ نہ ہو۔ یعنی یہ ایک تادیبی سزا ہے جو حاکم کسی جرم یا گناہ کے ارتکاب پر دیتا ہے۔‘‘(۴۹)
نتیجہ بحث
زنا اگر غیر مستوجب حد ہو، اور دیگر قرائن اور تعزیری نصابِ شہادت، جو کہ دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے پورا ہو جاتا ہے، اگر ارتکابِ جرم پایا جاتا ہو یا ایسا شبہہ جسے شبہہ ضعیفہ شمار کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گا، اور مقدمہ کی تفصیلات اور قرائنِ قویہ ثبوتِ جرم کے لیے موجود ہوں تو سقوطِ حد کے باوجود مجرم کو سزائے تعزیر دی جائے گی۔ البتہ یہ امر جج کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ مجرم کے ذاتی حالات اور معاشرتی پس منظر، حالات و واقعات کا بنظرِ غائر مطالعہ کرنے کے بعد سزا میں کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کے ضابطہ پر عمل کرے۔
زیربحث استفسار میں کہا گیا ہے کہ کیا زنا یا زنا بالجبر غیرمستوجب حد میں ملزم کو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں ملزم کے بجائے مجرم کا لفظ ہونا چاہیے۔ نیز اگر صرف زنا سے متعلق استفسار ہو گا تو زانی اور مزنیہ دونوں پر احکامِ بالا لاگو ہوں گے۔ اور اگر زنا بالجبر کے متعلق ہے تو مزنیہ بری ہو گی اور زانی کو سخت ترین تعزیری سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے بیک وقت دو جرموں کا ارتکاب کیا ہے: ایک ارتکابِ فاحشہ اور دوسرے جبر۔ ارتکابِ فاحشہ مستقل جرم ہے اور جبر مستقل جرم ہے۔ لہٰذا ایسے مجرم کی سزا بھی زنا بالرضا غیرمستوجب حد سے زیادہ ہو گی۔
حواشی
(۳۴) اخبار القضاء ج ۲ ص ۱۸۸ ۔ مصنف عبد الرزاق ج ۷ ص ۱۲۷ ۔ المحلیٰ لابن حزم ج ۱۱ ص ۳ و ۴
(۳۵) مصنف عبد الرزاق ج ۷ ص ۴۵۳ ۔ مسند الشافعی ج ۶ ص ۲۶۲
(۳۶) مصنف عبد الرزاق ج ۷ ص ۴۵۱
(۳۷) موسوعۃ فقہ عثمان، رداس قلعہ جی ص ۱۵۴
(۳۸) ج ۲ ص ۳۳۵
(۳۹) النساء ۳۴
(۴۰) تفسیرِ عثمانی، تفسیر ماجدی، تفسیر نعیمی
(۴۱) تبیین الحقائق ج ۳ ص ۲۵۸
(۴۲) الاحکام السلطانیہ ص ۲۳۶ ۔ اعلام الموقعین ج ۲ ص ۸۶ ۔ کشاف القناع ج ۶ ص ۹۸
(۴۳) فتاوٰی شامی ج ۳ ص ۱۹۴
(۴۴) المجتہدون فی القضاء ص ۸۷
(۴۵) بدائع الصنائع ج ۳ ص ۶۳
(۴۶) المحرر فی الفقہ ص ۱۶۳
(۴۷) المغنی مع الشرح الکبیر ج ۱۰ ص ۳۴۷
(۴۸) موسوعۃ فقہ عبد اللہ ابن مسعود، رداس قلعہ جی ۔ ص ۱۶۲
(۴۹) فقہ السنۃ ج ۲ ص ۴۹۷
مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
اکابرِ امت کی نظر میں
مولانا محمد عیسٰی منصوری
حضراتِ گرامی! آج ہم مفکرِ اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی زندگی، شخصیت، سیرت، علوم و افکار اور خدمات کے تذکرے، اور آپ کی زندگی اور کارناموں سے رہنمائی حاصل کرنے، انہیں مشعلِ راہ بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ اجلاس مفکرِ اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کے علوم اور عصرِ حاضر میں آپ کے فکری کام کے حوالے سے ایک اہم پیشرفت ہے۔
حضرت مولانا کی حیاتِ مستعار کے ۷۰ سالہ شب و روز اور آپ کی علمی و فکری جدوجہد کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
- ایک یہ کہ آپ نے مغربی فکر و فلسفہ کا گہرا تجزیہ کر کے مغربی افکار و نظریات اور تمدن و سیاست کی زہرناکی، اور پوری انسانیت کے لیے اس کی تباہ کاریوں پر مفصل و مدلل بحث فرمائی۔ اس کا سلسلہ ’’ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین‘‘ سے شروع ہو کر ’’اسلام اور مغربیت کی کشمکش‘‘، ’’نقوشِ اقبال‘‘ سمیت متعدد تصانیف اور سینکڑوں مضامین و تقاریر پر محیط ہے۔ اور شکر ہے کہ یہ سارا علمی ذخیرہ محفوظ ہے۔
- دوسرے آپ نے قرآن و سنت، اکابرینِ ملت اور ملتِ اسلامیہ کی تاریخ کی روشنی و رہنمائی پر نہایت سنجیدہ اور مثبت علمی انداز میں کام کیا۔ اس کا سلسلہ ’’سیرتِ احمد شہید‘‘، ’’تاریخِ دعوت و عزیمت‘‘ اور ’’اسمعیات‘‘ کے سلسلے سے شروع ہو کر ’’منصبِ نبوت‘‘، ’’نبیٔ رحمت‘‘، ’’ارکانِ اربعہ‘‘ اور سینکڑوں مقالات و مضامین کی صورت میں ہزارہا صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ عظیم ذخیرہ بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ عالمِ اسلام میں عصرِ حاضر کے مسائل، چیلنجز، مغرب کی تمدنی و فکری یلغار، علمی و فکری فتن کو جس شخصیت نے سب سے زیادہ سمجھا، محسوس کیا، اور اس کا علمی طور پر جواب تیار کیا، ملتِ اسلامیہ کے شعور کو بیدار کیا، نئی نسل کی رہنمائی کی، وہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ ہیں۔ اسی مناسبت سے بندہ نے اپنے مقالہ کا عنوان ’’صدی کی شخصیت‘‘ تجویز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موجودہ صدی میں ملتِ اسلامیہ کی علمی و فکری رہنمائی کا بنیادی کام آپ سے لیا۔ لیکن بعض کرم فرماؤں کے اصرار پر اب بندہ کے مقالہ کا عنوان ہے ’’مفکرِ اسلام سید ابوالحسن علی ندویؒ، اکابرِ امت کی نظر میں۔‘‘
حضراتِ گرامی قدر! حضرت مولانا جیسے مشاہیر کی زندگیاں تقویم کے ایام و شہور یا کسی کیلنڈر کے کسی چھوٹے بڑے دن میں پیدائش و وفات کے تعلق و تذکرے کی رہینِ منت نہیں۔ ان کی یاد کے لیے کسی خاص موسم یا فصلِ گل کی بھی ضرورت نہیں۔ ان کا وجود تاریخ کی ایک سچائی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کوئی موسم ہو، بہار و خزاں کا کوئی دور ہو، ان کی یاد ہماری تعلیم و تہذیب کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ ہم ان کے تذکرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔
یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند
بہار ہو کہ خزاں، لا الٰہ الا اللہ
حضراتِ گرامی قدر! ہم کسی شخصیت کی رسمی طور پر یاد منانے کے قائل نہیں۔ ہم تو اپنے اسلاف کی سیرت اور ان کے افکار کے محاسن کے جویا ہیں۔ ہم ان کے روشن کارناموں اور عظیم الشان خدمات کو مشعلِ راہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس عہدِ سعادت اور دورِ علم و تہذیب کی بازیافت کے لیے کوشاں ہیں جس کے سانچوں میں علم و عمل کے جامع اور ایثار و قربانی کے مجسمے اور اخلاق و سیرت کے یہ حسین پیکر ڈھلا کرتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے علوم و افکار سے ہمارے سینے معمور اور دماغ روشن ہوں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو۔ ان کے کارنامے اور ایثار ہمارے لیے مشعلِ راہ ہوں، یہاں تک کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں اپنے اسلاف کرام کی یادگار اور نمونہ بن جائیں۔ حضرت مولانا اسلام کے خدمتگاروں اور حق پرستوں کے جس قبیلے، ایثار پیشگانِ ملت کے جس قافلے، اور تجدیدِ احیاء اسلام کی تحریک کے جس سلسلۃ الذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس کی مختلف کڑیاں صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ کو محیط ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع اور اس سیمینار کے انعقاد کا مقصد مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کے علوم و افکار سے روشنی حاصل کرنا ہے کیونکہ عصرِ حاضر میں نئی نسل کے لیے علمی و فکری رہنمائی کا سب سے زیادہ ساز و سامان حضرت مولانا کی عملی زندگی اور آپ کی تصانیف میں موجود ہے۔
حضرت مولانا کی شخصیت میں فیضانِ الٰہی سے علم و عمل، فکر و سیرت، اخلاق و تہذیب کی بے شمار خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ آپ کے علم و فکر، تالیف و تدوین اور شرح و تفسیر، علوم و فنون اور خدماتِ ملتِ اسلامیہ کی جو خوبیاں دنیا پر ظاہر ہوئیں اور اصحابِ علم و نظر نے جن کا اعتراف کیا، وہ یہ نہیں کہ آپ ایک بلند پایہ عالمِ دین تھے، قرآن و حدیث اور تاریخِ عالمِ اسلام پر آپ کی گہری نظر تھی، خاص طور پر علومِ قرآن کے بے مثال عالم تھے، حکیم الہند امام ولی اللہ دہلویؒ کے علوم و معارف کے محقق و شارح تھے۔ آپ اپنی خدمات کی وجہ سے عالمِ اسلام کے دلوں کی دھڑکن بن گئے تھے۔ آپ کو من جانب اللہ جو عزت و توقیر اور قدر و منزلت عطا ہوئی وہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے اور واضح طور پر ’’سیجعل لہ الرحمٰن وُدّا‘‘ کی عملی تفسیر ہے۔ اس دور کے مختلف الخیال اصحابِ فضل و کمال میں ایسی ہمہ گیر مقبولیت کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کے یہاں علم کے موتیوں اور معرفت کے جواہر پاروں کی ایسی ریل پیل رہتی کہ جن کے لمحوں کو محفوظ کر لیں تو صدیاں فائدہ اٹھاتی رہیں۔ آپ موجودہ دور میں امام غزالیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ دہلوی کے علوم و افکار کا زندہ و تابندہ نمونہ تھے، جس کا نہ صرف ہم عصر بلکہ آپ کے اکابر و بزرگوں نے بھی دل کھول کر اعتراف فرمایا۔ یہی اعترافات اختصار کے ساتھ پیشِ خدمت ہیں۔
اس صدی کے سب سے بڑے مصلحِ امت اور شریعت و طریقت کے جامع حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک گرامی نامہ میں اس طرح مخاطب فرماتے ہیں:
’’بخدمت مجمع الکمالات زید لطفکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
فرحت نامہ پہنچا۔ ہر ہر لفظ حیات بخش تھا۔ جزاکم اللہ علٰی ہذا المحبۃ۔ آپ کے صدق و خلوص و سلامتِ فہم کے اثر سے میری طبعیت بھی دفعتاً آپ سے بے تکلف ہو گئی۔‘‘
حضرت حکیم الامتؒ کی محتاط و معتدل شخصیت سے ادنٰی واقفیت رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ حضرت کے ہاں محض رسمی طور پر یا تکلفاً القاب اور اعزاز و اعتراف کا رواج نہ تھا۔ ایک ۱۹ سالہ نوجوان عالمِ دین کو مجمع الکمالات لکھنا جہاں بہت بڑا اعزاز اور بڑی باوقار سند ہے وہیں مولانا کے متعلق حکیم الامت کے کمالِ فراست کی دلیل بھی ہے۔
اس صدی کے سب سے بڑے داعی الی اللہ امام التبلیغ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی نظر میں مولانا کا جو مقام و احترام تھا، اس کا کسی قدر اندازہ آپ کے ان مکتوبات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے مولانا کو تحریر فرمائے۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’مخدومی و مکرمی حضرت سید صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آں محترم کی توجہاتِ عالیہ سے تبلیغ کو جس قدر نفع پہنچا ہے اب تک لگنے والوں میں سے کسی سے نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مقدس توجہات کو اس طرف اور زائد سے زائد مبذول فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری کا انتظار ہے۔ توجہاتِ عالیہ اور دعواتِ صالحہ کا امیدوار ہوں۔
بندہ محمد الیاس غفرلہ
۲۷ اکتوبر ۱۹۴۳ء‘‘
ایک اورمکتوبِ گرامی کی ابتدا اس طرح فرماتے ہیں:
’’بخدمت عالی عمدۃ الآمال والامانی مکرم محترم جناب سید صاحب دام مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اس سے پہلے گرامی نامہ عالی شرف صدور لا کر بہت دنوں تک اپنے لیے وسیلۂ آخرت سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا رہا اور مکرر سہ کرر اپنی آنکھوں اور دل کو تسلی دیتا رہا ۔۔۔۔ میری امیدوں اور تمناؤں کے ودیعت گاہ محترم، سلالہ خاندانِ نبوت، جناب عالی کا مہمانانِ نبوت کو ساتھ لے کر اس کام کے لیے قدم مبارک اٹھانا جس قدر عظیم ہے اسی قدر اس کی وقعت ۔۔۔۔ میرا ضمیرشہادت دے رہا ہے کہ یہ کام دراصل آپ جیسے اہل اور خاندانِ نبوت ہی کے کرنے کا ہے۔ آپ کے قلوب سے جس قدر اس کےلیے شرحِ صدر کے ساتھ استقامت ظہور میں آتی چلی جائے گی اسی قدر گویا اس کے درست ہونے کی امیدیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی۔‘‘
ایک بار حضرت مولانا نے اپنے دہلی حاضر ہونے کی اطلاع دی تو رئیس التبلیغ مولانا الیاسؒ نے اس خوش خبری پر تحریر فرمایا:
’’جناب کی تشریف آوری مژدہ روئیں روئیں کو تر و تازہ کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں آپ کی ذاتِ گرامی سے مشفع فرمائیں۔‘‘
حضرت مولانا محمد الیاسؒ آپ کی خاندانی نسبت خصوصاً حضرت سید احمد شہیدؒ کے کس قدر معترف و معتقد تھے، اس کا اندازہ ایک مکتوب سے لگایا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں:
’’از سگِ آستانہ عزیزی و احمدی بندہ محمد الیاس عفی عنہ بسلالہ خاندانِ نبوت، جوہرِ تابانِ معدنِ سیادت، جناب سید صاحب دام مجدکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ایک اپنے خاندان کے ذرۂ بے مقدار خادم سے اپنے ذاتی جوہر اور حسنِ ظن کے سرمایہ کی بدولت کیسی خدمت وابستہ فرما دی۔ یہ بندۂ ناچیز نہ اس کا اہل ہے نہ بندہ کو مضامین پر دست رس ہے۔ لیکن عادۃ اللہ یہ جاری ہے ’’انا عند ظن عبدی بی‘‘۔ آپ جیسے حضرات کے حسنِ ظن کا بھی اثر ہو گا اور نتیجہ ہو گا کہ جو فیاضِ ازلی سے کچھ نصیب ہو جاوے گا۔‘‘
حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے وفات سے دو روز پہلے فرمایا:
’’مولانا میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ کی کیا تعریف کروں؟ تعریف کرنا محبت کا اوچھا پن ہے۔‘‘
پھر اچانک سر اٹھا کر مولانا علی میاںؒ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا:
’’اچھا جائیے، دولتِ قرآن مبارک ہو۔‘‘
دنیا جانتی ہے الشیخ الندویؒ کو قرآنی علوم و معارف، مطالب و مقاصد کے افہام و تفہیم کا ایک خاص نرالا و البیلا ذوق و ملکہ عطا ہوا تھا۔ کیا خبر یہ حضرت مولانا الیاسؒ کی دعاؤں اور توجہ کا اثر ہو۔
ایک بار مولانا شہر کے کسی تبلیغی گشت میں تشریف لے گئے تھے، حضرت مولانا الیاسؒ نے فرمایا:
’’ایک آدمی میری بات سمجھنے والا تھا، تم نے اس کو بھی بھیج دیا، اب میں کس سے بات کروں؟‘‘
حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے جانشین داعی الی اللہ امیرِ تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسفؒ ایک طویل خط میں لکھتے ہیں:
’’مخدوم و مکرم معظم جناب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرت عالی، مجھے دل سے اعتراف ہے کہ آپ نے حضرت مولانا مرحوم کی اس وقت قدر کی جس وقت یہ ناچیز ناقدری کر رہا تھا، اور آپ نے اس وقت عمل کی طرف قدم بڑھایا جس وقت یہ حقیر اس سے پہلوتہی کر رہا تھا۔ آپ سنتے تھے، تعمیل کرتے تھے، سمجھتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے، اور اس کام کے انہماک اور دعوت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت میں تاثیر دی، اضلاعِ متصلہ سے باہر یہ کام آپ ہی کی وساطت سے پھیلا اور علمی حلقوں میں آپ ہی کی وساطت سے یہ چیز پہنچی ۔۔۔۔ اگر حضرتِ عالی اپنے ان کمالات و فیوض سے، جو حضرت مرحوم کے ساتھ محبت و تعلق اور اس کام کی طرف سبقت و دعوت سے آپ کو حاصل ہیں، اور ساداتی جواہرات نے اس کو چار چاند لگائے ہیں۔ ہم خدام کو مستفید فرمائیں تو عین مراحم خسروانہ ہوں ۔۔۔۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ہفتہ عشرہ کے لیے تشریف لائیں تاکہ بقیہ تبلیغی حالات تفصیل سے سامنے رکھے جا سکیں۔ اس وقت ہم خدام کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔‘‘
حضرت مولانا ولیٔ کامل، عارف باللہ، مفسرِ قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے محبوب ترین اور معتمد ترین خلفا میں سے تھے۔ مولانا لاہوریؒ آپ سے اپنے حقیقی بیٹے کی طرح محبت فرماتے۔ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:
’’چونکہ آپ میرے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو فضل بھی آپ پر ہو، وہ میرے لیے باعث صد فخر ہے۔ مجھے جس طرح مولوی حبیب اللہ سلمہ کی ترقی سے فرحت ہو سکتی ہے اسی طرح، بلکہ بعض وجوہ کی بنا پر اس سے زیادہ خوشی اور سرور آپ کے درجات کی ترقی سے ہوتا ہے۔ اب یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور موجودہ دورِ فتن میں تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے، آمین یا الٰہ العالمین۔‘‘
حضرت لاہوریؒ ایک مکتوب میں رقم طراز ہیں:
’’میرے دل میں آپ کی جو عزت ہے، اسے ضبطِ تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اسی محبت و عزت کا نتیجہ ہے کہ میں نے حج کی رات مسجدِ خیف میں آپ کے درجات کی ترقی کے لیے بارگاہِ الٰہی سے استدعا کی اور الحمد للہ اس نے بارگاہِ الٰہی میں قبولیت پا لی۔‘‘
ایک اور مکتوب میں حضرت لاہوریؒ لکھتے ہیں:
’’(آپ کا خط پڑھا) تو اس میں آپ نے اپنی شرافتِ خداداد اور سعادتِ ازلی کے وہ موتی الفاظ کی لڑیوں میں پروئے ہیں جنہیں پڑھ کر بے ساختہ آپ کی صلاحیت و شرافت اور سعادت کی دل نے داد دی اور دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ! مولوی ابوالحسن صاحب کو اپنی رضا میں فنا کر کے دین کی خدمت کا بہت بڑا کام لے اور انہیں تادیر سلامت رکھ کر دین کی تبلیغ اور خلق اللہ کے باطن کی تربیت کی توفیق عطا فرما اور انہیں اخلاص و استقامت کے عطیات سے سرفراز فرما، آمین یا رب العالمین۔‘‘
حضرت لاہوریؒ کی طرح قطبِ وقت حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوریؒ سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت رائے پوریؒ کو جو آپ سےمحبت و انسیت اور تعلقِ خاطر تھا، اس کی شہادت حضرت رائے پوریؒ کے دوسرے محبوب خلیفہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ سے سنیے۔ حضرت مولانا نعمانیؒ ایک جگہ لکھتے ہیں:
’’اگرچہ یہ ناچیز ہی مولانا علی میاں کے جانے اور حضرت سے تعلق قائم ہونے کا اول ذریعہ بنا، حضرت سے بیعت کا شرف بھی پہلے ناچیز ہی کو حاصل ہوا، لیکن موصوف کی ان خداداد صفات اور خصوصیات کی وجہ سے، جن کی اللہ کے یہاں اور اس کے مقبول بندوں کے ہاں بھی زیادہ قدر و قیمت ہے، حضرت کے ہاں محبوبیت کا جو مقام ان کو حاصل ہوا وہ اس ناچیز کے لیے موجبِ حسرت ہونے کے باوجود ہمیشہ رشک و غبطہ کا باعث بنا رہا (ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء)‘‘
حضرت رائے پوریؒ نے ۲۸ نومبر ۱۹۵۶ء کے ایک مکتوب میں مولانا علی میاںؒ کو مخاطب فرماتے ہوئے مولانا رومؒ کے وہ اشعار تحریر فرمائے جو انہوں نے حضرت شمس تبریزؒ کے اشتیاق میں تحریر فرمائے تھے، اور تحریر فرمایا کہ
’’آپ کے آنے سے میری کٹھیا (خانقاہ) ایسے روشن ہو گئی جیسے شمس تبریز کے آنے سے مولانا رومؒ کے آستانے میں بہار آ گئی تھی۔‘‘
حضرت رائے پوریؒ کو مولانا کی ذات سے جو محبت و انسیت کے ساتھ ناز و افتخار کا تعلق تھا اس کا اظہار و ظہور زبانی، تحریری اور عملی طور پر ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب لاہور کے ایک عالمی اجلاس میں قادیانیت کے تعلق سے ایک عربی کتاب کی ضرورت محسوس کی گئی تو حضرت رائے پوریؒ نے بڑے اعتماد و افتخار کے ساتھ حضرت مولانا کا نام لے کر فرمایا کہ ’’وہ آئیں تو ہم ان سے چمٹ جائیں گے کہ یہ کام کر کے جاؤ‘‘
آپ کے شیخ حضرت رائے پوریؒ اپنے آخری حج ۱۹۵۰ء میں آپ کو خاص اہتمام و اصرار سے اپنے ساتھ لے گئے اور فرمایا کہ ’’یہ سفر میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔‘‘
مکہ مکرمہ میں آپ کے شیخ حضرت رائے پوری کی شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت مولانا دعوتی و تبلیغی مصروفیات سے فارغ ہو کر مستقر پر پہنچتے تو شیخ کو اپنا منتظر پاتے۔ انتظار و اشتیاق کا وہ انداز جیسے ماں اپنے بچے کے لیے سراپا انتظار ہوتی ہے۔ آتے ہی کھانے کے لیے فرماتے، کبھی کبھی خود اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر منہ میں رکھتے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں:
’’جب میں خیمہ میں قدم رکھتا تو دیکھتا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے رومال میں روٹیاں لپٹی ہوئی رکھی ہیں، مجھ کو دیکھ کر فرماتے، علی میاں! تم کو کھانے کا بھی ہوش نہیں، یہ دیکھو تمہارے لیے چپاتیاں لیے بیٹھا ہوں کہ خمیری روٹی تم کو نقصان کرتی ہے۔‘‘
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، جو آپ کے حدیث شریف کے استاذ بھی تھے، آپ کے بر اور مکرم ڈاکٹر عبد العلی صاحب کو ایک بشارت آمیز مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:
’’اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ کریم ساز موصوف (علی میاں) کو مفتاحِ خیر اور مغلاقِ شر بنائے۔ حضرت سید احمد شہیدؒ قدس اللہ سرہ العزیز کی تجدیدِ ملتِ اسلامیہ کی خدمتِ عالیہ کا علمبردار بنا کر نعمائے لدنیہ سے مالامال کرے، آمین۔ ننگِ اسلاف حسین احمد غفرلہ۔ ۱۵ ربیع الاول ۱۳۷۰ھ‘‘
حضرت شیخ الاسلام کی دعا کا اثر دنیا نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مولاناؒ سے اس صدی میں تجدیدِ ملتِ اسلامیہ کا کام لیا۔
اسی طرح ولیٔ کامل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنیؒ کی حضرت مولانا سے محبت و انسیت کا اندازہ ان بے شمار خطوط سے لگایا جا سکتا ہے جو حضرت شیخ نے تحریر فرمائے۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’بلا تصنع اور بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کرنا اپنا فریضہ اور آپ کا حق سمجھتا ہوں۔‘‘
۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ کو مدینہ منورہ سے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’دعاؤں سے نہ مکہ میں دریغ ہوا نہ مدینہ پاک میں۔ اور یہ بھی یاد نہیں کہ کسی دن آپ کے لیے صلوٰۃ و سلام پہنچانے میں تخلف ہوا ہو۔ اس سے تو آپ کو بھی انکار نہیں ہو گا کہ دل بستگی جتنی آپ سے ہے اتنی کسی سے بھی نہیں رہی۔‘‘
مولانا پر حضرت شیخ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ قیام کے زمانے میں مجلسِ ذکر میں جب صبح کو حاضری ہوتی تو روزانہ کا معمول تھا کہ عین ذکر کی حالت میں ایک چمچہ تلے ہوئے انڈے کا اور ایک خمیرہ کا مولانا کے منہ سے لگا دیا جاتا۔ اسی طرح حضرت شیخ اپنی عربی تصانیف پر باصرار حضرت مولانا سے مقدمہ لکھوایا کرتے تھے۔ مولانا کی اکثر تصانیف اپنی مجلس میں سنتے اور قدر افزائی فرماتے۔
جب امریکہ میں تقریروں کا مجموعہ ’’نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں‘‘ شائع ہوا تو حسبِ معمول حضرت شیخ نے اپنی مجلس میں پوری کتاب سنی اور خط تحریر فرمایا کہ اردو کے ساتھ انگریزی و عربی میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ تینوں زبانوں میں ایک لاکھ کے قریب نسخے چھپوا کر خوب تقسیم کرائے جائیں۔ اس کتاب کے دو ہزار نسخے حضرت شیخ نے خود خرید کر تقسیم فرمائے۔
حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الٰہ آبادی کو حضرت مولانا سے غایتِ محبت و شفقت رہی۔ جس طرح مائیں اپنے پیارے بچوں کو پاس بٹھلا کر کھلاتی ہیں، حضرت کبھی کبھی لقمہ بنا کر مولانا کے منہ میں رکھ دیتے۔ جب کبھی مولانا کے الٰہ آباد پہنچنے کی اطلاع ہو جاتی تو ناشتہ لے کر اسٹیشن پر منتظر رہتے۔ حضرت شاہ صاحبؒ بڑے صاحبِ کشف بزرگ تھے، ایک بار خاص کیفیت میں فرمایا:
’’سب کے دل دیکھ لیے، سب کے دل دیکھ لیے، لیکن جتنا صاف دل علی میاں کا دیکھا، ایسا کسی کا نہیں دیکھا۔‘‘
حضرت تھانویؒ کے خلیفۂ اجل اور مولانا کے محبوب استاذ حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ ایک جگہ مولانا کے متعلق یوں رقم طراز ہیں:
’’آج وہ سید ابوالحسن علی ندوی کے نام سے مشہورِ روزگار اور تبلیغِ دین کے کام میں پورے انہماک کے ساتھ مصروف ہیں۔ حجاز و مصر کی فضائیں ان کی دعوت کے نغموں سے مسحور ہیں ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے عربی تقریر و تحریر کی دولت ان کو عطا فرمائی ہے جس کو وہ بحمد اللہ دین کی راہ میں لٹا رہے ہیں۔‘‘
مفتی اعظم پاکستان اور حضرت تھانویؒ کے محبوب خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ حضرت مولانا کو موفق من اللہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت مفتی اعظم کے باتوفیق صاحبزادے حضرت مولانا جسٹس تقی عثمانی دامت برکاتہم ایک جگہ حضرت مولانا کے متعلق ان الفاظ میں اپنے احساسات لکھتے ہیں:
’’مفکرِ اسلام کی شخصیت ہمارے دور کی ان معدودے چند شخصیات میں سے ہے جن کے تصور سے نہ صرف اپنے زمانہ کے احساس میں کمی آتی ہے بلکہ ان کے صرف وجود ہی سے اس پُرفِتن دور میں تسلی اور ڈھارس کا احساس ہوتا ہے۔‘‘
جب حضرت مولانا کو ۱۹۵۵ء میں دمشق یونیورسٹی میں بطور استاذ تقرر کی نوید ملی تو اس اعزاز کی خبر پر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے شعبہ دینیات کے سربراہ اور اردو کے بے مثال ادیب حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ نے اپنے تاثر کا اظہار ان الفاظ میں کیا:
’’اخبار جمعیۃ کے بعد اخبار مدینہ میں بھی اس تاریخی امتیاز کی خبر پڑھی جو صدیوں بعد ہندوستان کو حاصل ہوا۔ علامہ صفی الدین بدایونی کے بعد شاید آپ دوسرے ہندی عالم ہیں جن کو شام میں پڑھانے اور اپنے علوم سے شامیوں کو فائدہ پہنچانے کا موقع ملا، بلکہ صفی ہندی تو خود گئے تھے اور آپ کو وہاں کی حکومت اور جامعہ نے طلب کیا ہے ’’وشتان بینھما‘‘۔ یہ امتیاز آپ کی شخصیت تک ہی محدود نہیں بلکہ سارے ہندی علما کے لیے سرمایۂ افتخار ہے۰‘‘
بھوپال کے حضرت شاہ یعقوب مجددیؒ آخری دور میں مجددیہ سلسلہ کے بڑے صاحبِ دل بزرگ ہوئے ہیں، آپ حضرت مولانا کا غایت احترام فرماتے۔ بایں ہمہ کمالات حضرت شاہ صاحب کا معمول تھا کہ مولانا کے لیے اسٹیشن پر تشریف لاتے، یہ صرف حضرت مولانا کا امتیاز تھا۔ بندہ نے آنکھوں سے دیکھا کہ امیر تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسفؒ بھوپال کے سالانہ عالمی اجتماع میں شرکت کے موقع پر پابندی سے حضرت کی مجلس میں شرکت فرماتے۔ ایک بار گاڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے رات کا بڑا حصہ حضرت کا اسٹیشن پر کٹا۔ حضرت مولانا نے خط میں اس پر ندامت کا اظہار کیا۔ شاہ صاحب نے جواباً مکتوب میں تحریر فرمایا:
’’اس عاجز کو جو روحانی آرام اس شب حاصل ہوا جس رات کو حضرت کے استقبال میں اسٹیشن پر رہا تھا، ایسی خوشی و فرحت کی کوئی رات مجھ کو اپنی زندگی میں یاد نہیں، جسمانی کوفت بہت قلیل اور روحانی فرحت بہت کثیر۔‘‘
عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھیؒ فرمایا کرتے تھے:
’’چونکہ علی میاں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں تو دوسرے پیروں کو مرید نہ ملیں۔‘‘
محدثِ شہیر جانشین حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ حضرت مولانا کو آیت من آیات اللہ فرمایا کرتے تھے۔
عارف باللہ صدیقِ زمانہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندویؒ اپنے آخری مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:
’’مخدومی حضرت اقدس دامت برکاتہم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
احقر کو اپنے اکابر سے الحمد للہ ہمیشہ سے عقیدت رہی ہے اور ہے۔ اس وقت حضرت والا کی عقیدت اور عظمت جو اس ناکارہ کے دل میں ہے، اس کو سب پر فوقیت اور اولیت حاصل ہے اور یہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اخیر وقت تک اس کو باقی رکھے۔‘‘
حضرت مولانا اشرف سلیمانی، خلیفہ حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں:
’’علی میاں کا خمیر محبت و نرمی سے عبارت ہے۔ علم و تقوٰی نے ان سے فروغ پایا ہے اور جامعیتِ علوم کی مسند ان سے مزین ہے۔ مشرق و مغرب کے دینی تقاضوں اور جدید طبقہ کے نبض آشنا ہیں۔ ان کی تحریر دلوں کے اندر اتر جاتی ہے اور بیک وقت دل و دماغ دونوں کو تسلی کا سامان مہیا کر دیتی ہے۔‘‘
حضرت مولانا کے دیرینہ رفیقِ محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحبؒ، جن کی حضرت مولانا سے نصف صدی سے زیادہ رفاقت رہی، عرصہ تک دن رات کا ساتھ رہا۔ معاصرت اور ایسی طویل رفاقت کے ساتھ حضرت نعمانی کی رائے و تاثر جتنا وقیع اور باوزن ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ تقریباً ۴۰ سال پہلے ۱۹۵۴ء میں دیوبند کے طلبا نے حضرت مولانا کو خطاب کی دعوت دی اور اس کے لیے حضرت مدنی سے سفارشی خط لکھوایا۔ آپ کے اس خطاب کو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے شعبان ۱۳۷۳ھ کے الفرقان میں شائع فرمایا اور اس خطاب پر اور حضرت مولانا کی شخصیت پر اپنا تاثر ان الفاظ میں قلم بند فرمایا:
’’یہ مقالہ اگرچہ مقالہ ہی ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اپنا یہ احساس و تاثر بے تکلف ظاہر کر دینے کو جی چاہتا ہے کہ اس عاجز کی نظر میں اس کی قیمت و اہمیت سینکڑوں صفحات والی بہت سی کتابوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس عاجز کا سن تو اگرچہ ابھی پچاس سے بھی کم ہے لیکن زندگی مختلف میدانوں میں ایسی رواں دواں گزری ہے کہ اتنی ہی عمر میں بہت کچھ دیکھ لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ تجربہ اور میری واقفیت اتنی ہے کہ اپنی اس رائے کے اظہار کا مجھے بجا حق ہے کہ ہماری اس دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی کم پیدا ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہنِ ثاقب بھی ملا ہو اور دلِ روشن بھی، جو اس دوڑتی ہوئی اور کروٹیں بدلتی ہوئی دنیا کے حالات و مزاج اور اس کے نت نئے تقاضوں سے پوری طرح باخبر بھی ہوں، اور دینی و ایمانی حقائق کے بارے میں وارثینِ انبیاء کرام کی طرح صاحبِ یقین بھی۔ الغرض ہماری اس دنیا میں یہ جنس بہت ہی کم یاب ہے۔ اور اللہ کے ایسے بندے جو ان دونوں صفتوں کے جامع ہوں، اس عاجز نے غالباً اتنے بھی نہیں دیکھے جتنی کہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ لیکن جو دو چار دیکھے ہیں ان میں ایک ذات رفیقِ محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی بھی ہے۔ اللہ کی خاص عنایت و توفیق سے وہ صاحبِ نظر و فکر بھی ہیں اور صاحبِ قلب بھی۔ اور اپنے علم و معلومات کے لحاظ سے جدید بھی ہیں اور ایمان و یقین اور رسوخ فی الدین اور طرزِ زندگی کے لحاظ سے قدیم بھی۔ ان کی ذات مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی۔‘‘
برصغیر ہی نہیں عالمِ اسلام بالخصوص عرب دنیا کے اساطینِ علم و فضل اور دینی و روحانی شخصیات نے جس فراخ دلی سے مفکرِ اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے، عصرِ حاضر ہی نہیں بلکہ شاید برصغیر کی پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ مفتیٔ اعظم فلسطین مفتی محمد امین الحسینی جیسی عظیم دینی اور مجاہد ہستی اپنے ایک مکتوب میں رقم طراز ہیں:
’’حضرت صاحب الفضیلۃ الاستاد الجلیل ابی الحسن علی الندوی وکیل ندوۃ العلماء بالھند۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کو ایک مومنِ مخلص کی شان کے مطابق مرض کی تشخیص اور اس کے لیے دوا تجویز کرنے کی سعادت و توفیق حاصل ہوئی۔‘‘
مفتی اعظم فلسطین کا یہ مکتوب ۲۷ جولائی ۱۹۵۷ء کا ہے جس میں آپ نے حضرت مولانا کے ایک نباضِ ملت ہونے اور آپ کی فکری اصابتِ رائے کا اعتراف فرمایا ہے۔
۱۶ سال کی عمر میں آپ کا مضمون ’’ترجمۃ الامام السید احمد بن عرفان الشھید‘‘ عالمِ اسلام کے جلیل القدر عالم و محقق علامہ سید رشید رضا نے اپنے معروف رسالہ ’’المنار‘‘ میں شائع کیا۔ پھر اجازت لے کر الگ سے کتابچہ کی صورت میں شائع کیا۔ حضرت مولانا کی یہ پہلی تصنیف تھی جو مصر سے عربی میں شائع ہوئی۔
حضرت مولانا کی عظیم و جلیل خدمات پر خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے ۱۹ اگست ۱۹۹۶ء کو ترکی میں جلسہ تکریم منعقد ہوا جس میں عالمِ اسلام کے جلیل القدر علماء و مفکرین نے آپ کی علمی و دینی خدمات پر مقالات پیش کیے۔ مصرکے مشہور عالم ڈاکٹر عبد المنعم احمد یونس نے اس سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا:
’’مولانا ابوالحسن علی ندوی پوری انسانیت کے مربی و محسن رہنما ہیں۔ عرب و عجم ان کی دعوت و فکر سے نہ صرف آشنا بلکہ ان کا قدردان ہے۔ آج ہمیں دلی مسرت ہے بلکہ ہم فخر و اعزاز محسوس کر رہے ہیں کہ استنبول جیسے تاریخی شہر میں ہم یہ جلسہ ایسی شخصیت کے اعزاز میں منعقد کر رہے ہیں جن کی ذات انجمن ساز ہے، جس نے اسلامی دنیا ہی نہیں مغربی دنیا کو بھی اپنی شخصیت و فن سے متاثر کیا ہے۔ بہت سے علمی و ادبی اور دعوتی مراکز کا سرچشمہ آپ کی ذات ہے۔‘‘
۱۳ نومبر ۱۹۹۷ء کو ندوۃ العلماء لکھنو میں قادیانیوں کے ارتدادی فتنہ کے خلاف عالمی پیمانہ پر اجلاس منعقد ہوا جس میں امام حرم الشیخ محمد عبد اللہ السبیل اور قبلہ اول مسجد اقصٰی کے امام و خطیب الشیخ محمد صیام نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ الشیخ سبیل حرمِ کعبہ کے سب سے بڑے امام اور حرمین شریفین کے تمام انتظامی و دینی امور کے صدرِ اعلٰی ہیں۔ حضرت مولانا کے ایما پر عالمی اجلاس کی صدارت کے لیے الشیخ محمد عبد اللہ السبیل کا نام تجویز ہوا تو شیخ نے فرمایا:’’سماحۃ الشیخ ابوالحسن علی کے ہوتے ہوئے میں صدر نہیں بن سکتا‘‘۔ چنانچہ امامِ حرم کے اصرار و خواہش پر حضرت مولانا ہی نے اجلاس کی صدارت فرمائی۔
عرب دنیا کے ممتاز عالم و خطیب اور مایہ ناز صاحبِ قلم الشیخ علی طنطاویؒ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’سیدی الاخ الحبیب فی اللہ الاستاذ الکبیر ابا الحسن علی الندوی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ایک دن میں ریڈیو والوں کو اپنی گفتگو براڈ کاسٹ کرا رہا تھا۔ براڈ کاسٹ کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا، کون سی جگہ آپ کو زیادہ پسند ہے اور کس جگہ سے آپ کی خوشگوار ترین یادیں وابستہ ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ جواب میں، میں اپنے شہر دمشق کا نام لوں گا (جو انبیاء کرامؑ، صحابہ کرامؓ اور کثیر اولیاء عظامؒ، شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ، ابن کثیرؒ، ابن عربیؒ وغیرہ کا مسکن و مدفن ہے اور خود حضرت مولانا کا محبوب ترین شہر ہے) لیکن جب میں نے لکھنو میں ندوۃ العلماء کا نام لیا تو وہ حیران رہ گیا۔ تعجب سے پوچھا، لکھنو کیا ہے؟ میں نے جواب دیا الشیخ ابوالحسن علی کا شہر۔‘‘
اپنے دور کے عظیم محدث، فقہ حنفی و حدیث کے امام، کثیر کتب کے مولف الشخ عبد الفتاح ابو غدہؒ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
’’یحیٰی بن سعید حدیث بیان فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ موتیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ واللہ آپ کی باتیں بھی ہمارے لیے ایسی ہی ہیں۔ شکر اس خدا کا جس نے آپ کو یہ نعمت دی اور اس پر قادر بنایا اور اس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ اور آپ کی شخصیت میں ہماری تاریخ کے روشن و شاندار علمی صفحات دکھائے، عالی مرتبت علماء سلف کی یاد تازہ کی۔ آپ کی ذاتِ گرامی الحمد للہ ان اسلاف کو یاد دلانے کا بہترین نمونہ ہے۔‘‘ (ریاض۲۰۔۴۔۱۴۰۲ھ)
عرب دنیا کے مشہور عالم و محقق، قطر یونیورسٹی کی کلیۃ الشریعہ کے سربراہ، فقہ الزکوٰۃ جیسی متعدد علمی کتب کے مصنف، دینی خدمات میں فیصل ایوارڈ یافتہ، عظیم داعی و خطیب الشیخ یوسف القرضاوی ۱۹۹۵ء میں حضرت مولانا کے دوحہ قطر تشریف آوری کے موقع پر اپنی تعارفی تقریر میں فرماتے ہیں:
’’الشیخ ابوالحسن علی ندوی ایک عظیم اسلامی شخصیت ہیں۔ وہ سر تا پا اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اسلام ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا ہے۔ اسلام ہی ان کی ابتدا و انتہا ہے۔ آپ صحیح معنی میں محمدی ہیں بایں طور کہ آپ نے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، اور پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق ہی کو اپنایا ہے۔ آپ اس دور میں سلف صالحین کا نمونہ اور ان کی سچی یادگار ہیں۔ آپ کو دیکھنے سے حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ شیخ کے یقینِ کامل، اللہ پر حقیقی توکل اور امت کی فکر میں ان کی تڑپ اور اپنے آپ کو گھلانے نے مجھے ان کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ میں ان کی محبت سے اللہ کے قرب کا امیدوار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ حشر میں مجھے ان کا ساتھ نصیب ہو۔‘‘
عرب دنیا کے مایہ ناز عالم و محقق شیخ الازہر الشیخ ڈاکٹر عبد الحلیم محمود اس طرح اعتراف فرماتے ہیں:
’’الشیخ ابوالحسن علی ندوی، آپ نے اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دی ہے اور اپنے شب و روز ایک مخلص و متقی مسلمان کی طرح گزار رہے ہیں۔ آپ نے پاکیزہ اسلوب و کردار اور عمدہ اسلامی لٹریچر کے ذریعے سے اسلام کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا ہے۔‘‘
نصف صدی پہلے ۱۹۵۰ء میں سعودی ریڈیو نے حضرت مولانا کی شخصیت پر ایک تفصیلی خاکہ پیش کیا جو تقریباً دس صفحات کو محیط ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ حسبِ ذیل ہے:
’’ہم سامعین کے سامنے عصرِ حاضر کی ایک ایسی جامع الصفات اور منفرد شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ و آئیڈیل ہے۔ یہ شخصیت گزشتہ زمانوں کے لحاظ سے بھی قابلِ تقلید ہے اور ہر زمانہ ہر جگہ کے لیے موزوں و مثالی شخصیت ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی، جوہرِ نایاب، اور وہ عبقری انسان ہے جن کے دل میں انسانیت کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ آپ ایسے پارسا اور دین دار ہیں جنہیں دیکھ کر سلف صالحین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی ایک نابغہ عصر اور نادرۂ روزگار شخصیت ہیں جن کی عبقریت مسلم ہے۔ جس پہلو سے بھی ہم دیکھتے ہیں انہیں عظیم و مثالی پاتے ہیں۔ ان کی عظیم المرتبت شخصیت عصرِ حاضر کے لیے فخرِ قوم و ملت اور فخرِ اسلام ہے۔‘‘
جس وقت سعودی ریڈیو آپ کی زندگی کی جھلکیاں پیش کر رہا تھا اس وقت آپ کی عمر محض ۳۵ سال تھی۔ اس کے بعد نصف صدی تک اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کے مختلف شعبوں میں احیاء دین کا کام لیا حتٰی کہ آپ کی شخصیت پورے عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر محبوب ترین ہستی بن گئی۔
ہم اس دعا پر اس مقالہ کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مولانا کے گراں قدر علمی سرمایہ اور تصانیف سے فائدہ اٹھانے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
مولانا مفتی محمودؒ کا فقہی ذوق و اسلوب
معاصرین کی نظر میں
مفتی محمد جمیل خان
مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود قدس اللہ سرہ العزیز اپنے وقت کے ممتاز سیاسی قائد ہونے کے ساتھ ساتھ صفِ اول کے محدثین اور فقہاء میں شمار ہوتے تھے اور علمی مآخذ کے ساتھ ساتھ دورِ حاضر کی ضروریات اور مسائل پر گہری نظر رکھنے کی وجہ سے ان کے فتاوٰی کو اہلِ علم میں اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں دارالافتاء کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے ہزاروں فتوے جاری کیے جن کی اشاعت کی ضرورت ایک عرصہ سے محسوس کی جا رہی تھی۔ جمعیۃ پبلیکیشنز جامع مسجد پائلٹ سکول وحدت روڈ لاہور نے حافظ محمد ریاض درانی کی مساعی سے ان فتاوٰی کی اشاعت کا آغاز کیا ہے اور ’’فتاوٰی مفتی محمود‘‘ کے نام سے اس علمی ذخیرہ کی پہلی جلد منظرِ عام پر آ چکی ہے جو عقائد، طہارت، احکامِ مساجد، اذان اور مواقیت الصلوٰۃ کے اہم مسائل پر مشتمل ہے اور سوا چھ سو سے زائد صفحات کو محیط ہے۔ آغاز میں مولانا مفتی محمد جمیل خان کا ایک سو صفحات پر مشتمل طویل مقدمہ ہے جس میں فقہ کی ضرورت و تدوین، فقہ حنفی کی خصوصیات، اور حضرت مفتی صاحبؒ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ان کے بعض معاصرین کے تاثرات شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض تاثرات کا خلاصہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)
حضرت مولانا خان محمد صاحب
مفتی صاحبؒ میرے مخدوم و مکرم تھے، ان سے تعلق بھی پرانا تھا اور رشتۂ محبت بھی قدیم۔ پہلی ملاقات ۱۹۵۳ء میں ہوئی۔ حضرت والدِ محترمؒ اس وقت بقیدِ حیات تھے۔ مفتی صاحبؒ کو انہوں نے کندیاں شریف بلایا تھا۔ ان کی آمد یہاں ایک فتوے کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں دو خاندانوں کا مسئلہ طلاق پر باہمی جھگڑا تھا۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، ایک فریق کہتا تھا طلاق ہو گئی ہے اور دوسرا اس سے مختلف موقف رکھتا تھا۔ علاقے کے علماء کرام اور مفتیانِ عظام اس مسئلے پر اپنی رائے پیش کر چکے تھے لیکن جھگڑا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ غالباً یہ لوگ حضرتؒ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ ان کی نظر میں جو مفتی سب سے زیادہ قابلِ اعتماد ہو اس کا نام پتا بتا دیں۔ حضرتؒ نے مفتی محمودؒ کا نام تجویز کیا اور خود ہی ان کو کندیاں شریف اپنا مہمان بنا کر بلایا۔
مفتی محمود صاحبؒ نے مقامی علماء سے بات چیت کی، فریقین کا موقف معلوم کیا، پھر فریقین کی براہِ راست بات سنی، ان کے موجودہ اور سابقہ موقف کا موازنہ کیا، پھر جب وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے تو اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ ان کا فیصلہ وہی تھا جو دوسرے علماء پہلے دے چکے تھے لیکن طریقِ معلومات اور طرزِ استدلال انوکھا تھا۔ چونکہ وہ اس وقت نوجوان تھے، زیادہ پختہ عمر نہیں تھے، اس لیے مقامی علماء میں ان کی ذات موضوعِ گفتگو بن گئی۔
اس بحث میں ان کے معاصرین ان کی علمی لیاقت پر اظہارِ حیرت کر رہے تھے۔ بعض حضرات نے ہمارے حضرتؒ سے سوال کیا کہ آپ کی نظر انتخاب ان پر پڑنے کا کیا سبب ہے؟ حضرتؒ نے اس وقت علماء کو جو مختصر سا جواب دیا تھا وہ یہ تھا:
’’یہ گوہرِ قابل ہے، اس کی حفاظت کرو، اس پر نظر رکھو، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا کام لے گا۔‘‘
حضرت مولانا مفتی احمد الرحمٰنؒ
حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھی۔ ایک ایک گوشہ ایسا تھا جو کہ سب کو متاثر کر دیتا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ جامع شخصیت کے مالک تھے، ایک طرف سیاسی میدان کے شہسوار، دوسری طرف تدریس کے لیے مایہ ناز، اور تیسری طرف طریقت کے بے مثل شیخ۔ یہی جامعیت ہم نے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو سیاست اتنی گندگی اور جھوٹی نہ تھی جتنی کہ موجودہ دور میں ہو گئی ہے۔ اب عام طور پر یہ تاثر ہے کہ کوئی شخص سیاست میں رہ کر شریف، سچا اور دیانتدار نہیں رہ سکتا، مگر حضرت مولانا مفتی محمود صاحبؒ نے ایک ایسا نمونہ چھوڑ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی امداد شاملِ حال ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنا لے تو اس راستے پر بھی وہ اپنا دامن بچا کر چل سکتا ہے۔
حضرت مفتی صاحبؒ نے اس گندے ماحول میں اپنے آپ کو دین پر نہ صرف قائم رکھا بلکہ کسی بھی لمحہ تقوٰی اور پرہیزگاری کو نہیں چھوڑا۔ اس کی وضاحت ایک واقعے سے ہو جائے گی۔ حضرت مفتی صاحبؒ صوبہ سرحد کے وزیراعلیٰ تھے، ان دنوں سرحد بینک میں بڑی ملازمت کی جگہ خالی ہوئی جس کے لیے غالباً اخبار میں اشتہار چھپا۔ میں کراچی میں تھا۔ ایک دوسرے میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ اس بینک کی ملازمت کے لیے آپ مفتی محمود صاحب کے پاس سفارش کے لیے چلیے، میں نے اس سے کہا کہ جانے سے پہلے میں مفتی صاحب سے ٹیلیفون پر بات کروں گا، اگر انہوں نے کہا کہ آجاؤ تو چلا جاؤں گا ورنہ میرا ٹیلیفون ہی ہو گا۔ بہرحال میں نے حضرت مفتی صاحبؒ سے فون پر بات کی، انہوں نے فرمایاکہ بینکنگ کا شعبہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ فاروق صاحب کے پاس ہے، میں اس میں زیادہ سے زیادہ سفارش کر سکتا ہوں، مگر ایک بات پہلے تم سے پوچھتا ہوں، اگر تم نے بحیثیت مفتی اثبات میں جواب دیا تو پھر سفارش کروں گا ورنہ نہیں۔ پھر سوال کیا کہ شرعی حکم کے مطابق کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ میں نے جواب دیا کہ آپ خود مفتی ہیں، آپ بہتر فتوٰی دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحبؒ نے کہا کہ نہیں، تم فتوٰی دو۔ اگر تم نے فتوٰی دے دیا تو میں اپنے فتوے کو چھوڑ کر تمہارے فتوے پر عمل کروں گا۔ مفتی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں بینک کی نوکری کو ناجائز سمجھتا ہوں اور جو چیز ناجائز ہو اس کی سفارش کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔
بہرحال میں نے اس شخص کو پوری بات بتا دی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے اس نوکری کا ارادہ ترک کر دیا۔ دیکھئے اس مرحلے پر بھی آپ نے شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، حالانکہ یہ ایسا مسئلہ تھا جس میں تاویل اور ہیرپھیر کی گنجائش نکل سکتی تھی مگر آپ نے اس موقع پر بھی تقوٰی پر عمل فرمایا۔
حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ
حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت پاکستان میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میری نظر سے آج تک کوئی ایسا عالم نہیں گزرا جس نے فقہ کی کتاب شامی (جو کہ آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد میں سات سو صفحات ہیں) کا بالاستیعاب ایک دفعہ بھی مطالعہ کیا ہو، مگر مفتی صاحب نے اس کتاب کو بالاستیعاب تین دفعہ اول سے آخر تک پڑھا اور ان کو اس کتاب پر مکمل عبور حاصل ہے، کسی مسئلے پر آپ کے فتوے کے بعد کسی دوسرے فتوے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔
امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ
ایک مجلس میں جب شاہ جیؒ نے اپنے مخصوص قلندرانہ انداز میں کہا:
’’ہائے! اس قوم کی بدقسمتی اور اس شخص کی بدقسمتی‘‘۔
تو حاضرین حیرانی سے شاہ جیؒ کا منہ دیکھنے لگے۔ ہر شخص کا سوالیہ نشان بن کر سوچنے لگا کہ خدا جانے شاہ جیؒ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں۔ پھر شاہ جی کے چہرے پر تفکرات کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ وہ دیر تک خاموش، گم صم اور کھوئے سے رہے۔ پھر حاضرین پر ایک نظر ڈال کر فرمایا:
’’تم نہیں جانتے مولوی محمود کون ہے؟ یہ بڑا قیمتی آدمی ہے۔ یہ شخص ہمارے دور کا انسان تھا، اس دور میں پیدا ہو گیا، یہی اس کی بدقسمتی ہے۔ ہم خوش قسمت تھے کہ اس دور میں پیدا ہوئے جب اچھے لوگوں کی کمی نہیں تھی، ہمیں اچھے ساتھی میسر آ گئے۔ اب جو دور آ رہا ہے اس میں اچھے لوگ مفقود ہیں۔
جو بادہ خوار پرانے تھے، اٹھتے جاتے ہیں
خدا جانے اس شخص کو اچھے رفقا میسر آئیں نہ آئیں۔ قدرت نے اسے کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اسی سانچے میں ڈھلا ہوا انسان ہے جس میں بڑے لوگ ڈھلا کرتے تھے۔ مگر اب تو وہ سانچہ ہی ٹوٹ گیا، اب بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ نہ جانے اس شخص کے چہرے پر مجھے مستقبل کا نوشتہ کیسے نظر آ رہا ہے؟‘‘
پھر شاہ جی ایک شخص کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئے:
’’میرے بھائی! یہ اس دور کا انسان نہیں۔ خدا اس کی حفاظت کرے۔ تم لوگ بھی اس شخص کا خیال رکھو۔ یہ محمود بھی یقیناً کوئی سومنات ہی توڑے گا۔‘‘
جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی
حضرت مفتی محمود صاحب کا اسمِ گرامی میں نے سب سے پہلے اپنے ایک استاذ مکرم سے سنا تھا۔ اس وقت حضرت مفتی محمود مدرسہ قاسم العلوم میں استاذِ حدیث اور مفتی کے فرائض انجام دیتے تھے اور عملی سیاست میں داخل نہ ہوئے تھے۔ ہمارے استاذِ مکرم نے ان کی علمی بصیرت اور فقہی نظر کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد احقر کو پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف وفاق المدارس کے ایک سالانہ اجلاس میں حاصل ہوا جس میں احقر اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا اور پہلی ہی ملاقات میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی علمی بصیرت، ان کی متانت و سنجیدگی، اور ان کے دل کش اندازِ گفتگو کا ایک گہرا نقش دل پر ثبت ہو گیا۔
اس کے بعد بارہا مفتی صاحب سے شرفِ ملاقات حاصل ہوا اور ہر مرتبہ اس تاثر کی تائید و تقویت ہی ہوتی چلی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے علمی مقامِ بلند کا احترام دل میں ہمیشہ جاگزیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نادر صلاحیتوں سے نوازا تھا، ان کی عظمت کا احساس دل سے کبھی محو نہیں ہوا۔ ہم نے انہیں علمی اعتبار سے ہمیشہ اپنے استاد کے برابر سمجھا اور انہوں نے بھی ہمیشہ بزرگانہ شفقت و محبت کا برتاؤ فرمایا۔
حضرت مولانا عبید اللہ صاحب (مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور)
مفتی صاحب نے پہلی ملاقات میں مجھ سے ایسی بہت سی باتیں کیں جن سے میرے دل کو تسلی ہوئی۔ مجھے اس بالمشافہہ گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ مفتی صاحب اپنے دل میں اتحاد بین المسلمین کے لیے بڑی تڑپ رکھتے ہیں اور فرقہ واریت سے انہیں طبعی نفرت ہے۔ چونکہ اس وقت وہ نوجوان تھے اس لیے ایک نوجوان عالم کی زبانی اتنی سنجیدہ اور فکر انگیز گفتگو میرے لیے خوشی کا باعث بنی۔ نوجوان عموماً جذباتی ہوتے ہیں، ان کی سوچ بھی جذباتی ہوتی ہے، ان کے فیصلے بھی جذباتی ہوتے ہیں، مجھے اطمینان ہوا کہ ہمارے ہم عمر علماء میں وہ ایک پختہ فکر، صائب الرائے اور زیرک انسان ہیں۔ ان کی یہی صفت میرے دل کو زیادہ بھائی۔
اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان ملاقاتوں میں علمی، سیاسی اور ملی مسائل کے علاوہ بین الاقوامی مسائل بھی زیربحث آتے رہے اور ان کی فقہی رائے کو میں نے ہمیشہ قوی پایا۔ بعض مسائل میں وہ اپنی انفرادی رائے بھی رکھتے تھے، ایسی رائے کے حق میں ان کے پاس قوی دلائل ہوتے تھے۔
مثال کے طور پر فقہی مسائل پر عمل کے سلسلے میں ان کی رائے یہ تھی کہ مخصوص حالات میں ایک حنفی کے لیے جائز ہو گا کہ وہ کسی خاص مسئلے میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی کر لے۔ ایسا آدمی ان کے نزدیک حنفیت سے خارج نہیں ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امام محمدؒ اور امام یوسفؒ نے متعدد مسائل میں امام صاحبؒ سے اختلاف کیا ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں لیکن ان پر حنفیت سے خروج کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ اپنے اختلافات اور ترجیحات کے باوجود حنفی تھے۔ اسی طرح اگر کسی مسئلے میں امام صاحبؒ کا قول موجود نہ ہو، یا قول تو موجود ہو مگر سمجھ نہ آئے، یا سمجھ بھی آئے لیکن حالات کی خاص نوعیت کے تحت اس پر عمل نہ ہو، تو کسی دوسرے امام کی پیروی درست ہو گی۔
اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایسی مشکل صورت پیش آ جائے تو صاحبین کے قول پر عمل کیا جائے۔ اگر صاحبین کے قول میں بھی یہی صورت پیش آ جائے تو امام محمدؒ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ اس کے بعد درپیش مسئلے میں ائمہ اربعہ میں کسی ایک کے اقرب قول پر عمل کر لیا جائے۔ ان کے نزدیک کسی خاص مسئلے میں خاص حالات میں خروج عن الحنفیت تو جائز ہے لیکن مذاہب اربعہ سے خروج جائز نہیں۔
اس نقطۂ نظر میں مفتی صاحبؒ منفرد تھے تاہم وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ ایسا کرنا ان علماء کا کام ہے جن کی مذاہبِ اربعہ پر وسیع نظر ہے، جو کسی مسئلے کے ترجیحی پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرے، کیونکہ ایسی اجازت دینے سے اس کے عقیدے میں خلل آ سکتا ہے۔ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ادھر ادھر بھٹکنے کے عادی بن سکتے ہیں۔ جبکہ ایسی صورت صرف اسی وقت پیش آ سکتی ہے جب ملکی قوانین کی تدوین کے سلسلے میں علماء کسی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ اصل چیز کسی امام کا قول نہیں، اصل چیز وہ نص ہے جس کی روشنی میں یہ قول متشکل ہوا، یعنی منصوص چیزیں جو ائمہ کرام کی علمی تحقیقات کے نتیجے میں معلوم ہوئیں۔ ائمہ اربعہ نے بے پناہ تحقیق و جستجو کے بعد قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کیے ہیں، اس لیے باور کیا جا سکتا ہے کہ کسی مسئلے پر اگر احناف کے ہاں کوئی دلیل یا سند نہیں مل سکتی تو دوسرے مذاہب سے اسے لینا درست ہو گا بشرطیکہ وہ وہاں بہتر صورت میں موجود ہو۔
حضرت مولانا صدر الشہیدؒ
قاسم العلوم میں ان کے ابتدائی دور میں لوگ ہزاروں مسائل لے کر آئے اور انہوں نے ہزاروں فتوے جاری کیے۔ ان میں بیشتر مسائل مشکل اور الجھے ہوتے تھے لیکن مفتی صاحبؒ کے دستِ گِرہ کُشا کے سامنے یہ الجھاؤ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ چونکہ اس مدرسے میں مفتی صاحبؒ اس شرط پر آئے تھے کہ انتظامیہ ان کی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائے گی، اس لیے جب مفتی صاحبؒ کی سیاسی مصروفیات بڑھ گئیں تو افتاء کا کام کم ہو گیا۔ اب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو مفتی صاحبؒ اس پر فتوٰی دیتے، عام مسائل پر نائب مفتی ہی جواب لکھ دیتے تھے۔
میری معلومات کے مطابق ایسا بہت کم ہوا ہے کہ مفتی صاحبؒ کو کسی مسئلے پر پریشانی ہوئی ہو۔ اور ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ان کے قلم سے کوئی فتوٰی نکلا ہو اور بعد ازاں اس پر انہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ فتوٰی صادر کرنے سے پہلے متعلقہ مسائل کی تمام کلیات و جزئیات کو سمجھتے تھے، اس کے بعد اس موضوع پر جملہ کتب کو سامنے رکھتے تھے، تب جا کر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس مسئلے پر کیا فتوٰی دینا درست ہو گا۔
حضرت مولانا محمد اجمل خان
مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عہدِ حاضر کے ان علماء اور محققین کے سرخیل تھے جن کے علمی اور سیاسی وجود پر نہ صرف برصغیر بلکہ تمام عالمِ اسلام فخر کر سکتا ہے۔ وہ ایک ہمہ صفت انسان اور عجیب و غریب خوبیوں کے مالک تھے۔ قدرت نے انہیں اتنی اعلیٰ اور منفرد خصوصیات سے نوازا تھا کہ علم و دانش کے اس بحرِ بے کراں کا علمی استحضار بڑے بڑے علماء کے لیے قابلِ رشک تھا۔ ان کی فاضلانہ بصیرت مُسلّم تھی۔ وہ بیک وقت مفسرِ قرآن، محدثِ زمان، فقیہِ دوران اور عربی کے قادر الکلام مقرر تھے۔ انہوں نے مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں منصبِ افتاء پر فائز ہو کر تقریباً بائیس ہزار فتوے صادر کیے اور کسی ایک فتوے پر بھی کوئی عالم یا مفتی انگشت نمائی نہ کر سکا۔ ترمذی شریف کی عربی شرح ان کا علمی شاہکار ہے۔ مفتی صاحبؒ عالمِ اسلام کے چند بڑے علماء میں سے ایک تھے۔
تفقہ، تدبر، انجام بینی اور دور اندیشی میں آپ کو ممتاز مقام حاصل تھا۔ عالمِ اسلام کے محدثِ اعظم، عارف باللہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری قدس سرہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحبؒ کو ’’فقیہ النفس‘‘ فرمایا کرتے تھے۔ تفقہ اور فہمِ دین آپ کا طبعی و فطری وصف تھا۔ معاملہ فہمی، حقیقت شناسی کا جوہر قَسامِ ازل نے آپ کی طبیعت میں ودیعت کر دیا تھا۔ آپ نے تقریباً تیس سال مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دارالافتاء کو زینت بخشی، قدیم و جدید مسائل پر ہزاروں فتوے آپ کے قلم، آپ کے مشورے یا آپ کی سرپرستی میں لکھے گئے جن کی نقول مدرسہ قاسم العلوم کے دارالافتاء میں محفوظ ہیں۔
چند علمی مسائل کی وضاحت
محمد عمار خان ناصر
’’الشریعہ‘‘ کے جولائی اور اگست ۲۰۰۱ء کے شماروں میں شائع ہونے والی میری تحریروں کے حوالے سے جدِ مکرم استاذِ گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم نے بعض امور کی طرف توجہ دلائی اور ان کی وضاحت کی ہدایت کی ہے۔ میں استاذِ گرامی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی پیرانہ سالی، علالت اور ضعف کے باوجود ازراہِ شفقت ایک طالب علم کی آرا پر تنقیدی نظر ڈالنے کی زحمت فرمائی اور اپنی علمی رہنمائی سے بعض آرا پر ازسرِنو غور و فکر اور بعض کی اصلاح کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو صحت و عافیت اور تندرستی سے نوازے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، آمین۔
ان امور کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:
(۱) ’’الشریعہ‘‘ کے جولائی ۲۰۰۱ء کے شمارے میں ’’اسلام میں عبادت‘‘ کے عنوان سے میری ایک تحریر شائع ہوئی ہے جس میں، میں نے عرض کیا ہے کہ اگرچہ نماز کا بنیادی ڈھانچہ دین میں متعین کر دیا گیا ہے، تاہم اس کے بعض اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا یا نہ کرنا لوگوں کے انفرادی ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں جن امور کا میں نے تذکرہ کیا، ان میں رفع الیدین، وضع الیدین، آمین بالجہر اور فاتحہ خلف الامام جیسے مسائل بھی شامل ہیں جو صدیوں سے اہلِ علم کے مابین مختلف فیہ چلے آ رہے ہیں۔ استاذِ گرامی کا ارشاد ہے کہ اہلِ علم کے نزدیک یہ مسائل ذوقی نہیں بلکہ علمی اور تحقیقی ہیں اور ہر فریق اپنے دلائل کی بنیاد پر جس رائے کو درست سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔
مجھے اس سے اتفاق ہے کہ امرِ واقعہ یہی ہے۔ میری مذکورہ رائے محض مخالف روایات کی توجیہ کی ایک کوشش ہے ورنہ خود میرا اطمینان اور عمل ان مسائل میں احناف کے مسلک پر ہے۔(۱)
(۲) ’’الشریعہ‘‘ کے اگست ۲۰۰۱ء کے شمارے میں ’’غیر منصوص مسائل کا حل‘‘ کے زیرعنوان میرا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں فقہِ اسلامی کے اصولوں کی روشنی میں بعض جدید پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ استاذِ گرامی نے اس ضمن میں جن محلِ اشکال امور کی نشان دہی کی ہے، ان کی تفصیل سے پہلے اس بات کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں کہ مذکورہ تحریر میں اختیار کی جانے والی آرا کسی قسم کے ادعا کے بغیر محض طالب علمانہ آرا ہیں۔ ان سے غرض نہ یہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے کہ قارئین ان میں سے کسی رائے کو اپنے معتمد اہلِ علم کی رائے کے خلاف پائیں تو اسے چھوڑ کر میری رائے پر عمل کریں۔ حاشا و کلّا۔
مذکورہ مضمون کے آغاز میں، میں نے صراحتاً عرض کیا تھا کہ:
’’فقہی و علمی مسائل میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اہلِ علم کے مابین اختلافِ رائے کا واقع ہو جانا ایک بالکل فطری امر ہے۔ چنانچہ تمام علمی آرا کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ان آرا کو ترجیح دی ہے جو میرے ناقص فہم کے مطابق، ازروئے اصول و قواعد، اقرب الی الصواب ہیں۔‘‘
میں نے اپنے امکان کی حد تک غور و فکر کے بعد اس جذبے کے ساتھ بعض آرا قائم کیں کہ اگر کسی بھی وقت ان میں فہم و استدلال کی غلطی واضح ہو جائے تو کسی تامل کے بغیر ان سے رجوع کر لیا جائے۔ چنانچہ استاذِ گرامی کی نشان دہی پر سرِدست جن مسائل کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں ان کی تفصیل عرض کر رہا ہوں:
۱۔ جڑواں بہنوں کے نکاح کے ضمن میں، میں نے لکھا تھا:
’’اگر دو عورتیں اس طرح پیدا ہوئی ہوں کہ ان کے اعضا ایک دوسرے کے ساتھ ناقابلِ انفصال طریقے پر جڑے ہوئے ہوں تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ عقلاً اس میں تین احتمال ہیں: یا تو وہ دونوں مجرّد رہیں، یا دونوں کا نکاح دو الگ الگ مردوں سے کر دیا جائے، اور یا دونوں کو ایک ہی مرد کے نکاح میں دے دیا جائے۔ ان میں سے تیسری صورت میں پہلی دو صورتوں کی بہ نسبت کم قباحت اور ضرر پایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اسی کو اختیار کیا جائے گا۔‘‘ (ص ۲۵)
میں نے یہ رائے ’’یختار اھون الشرین‘‘ (کم ضرر والا راستہ اختیار کیا جائے) کے اصول پر قائم کی تھی لیکن دوبارہ غور کرنے کے بعد دیانت داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کم ضرر والی صورت تیسری نہیں بلکہ پہلی ہے یعنی یہ کہ دونوں بہنیں مجرّد رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع بین الاختین کی حرمت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے اور ایسی حرمت میں استثنا صرف ایسے عذر کی صورت میں ماننی چاہیے جو کثیر الوقوع ہو، جبکہ مذکورہ صورت نادر الوقوع بلکہ قریب قریب عدیم الوقوع ہے۔ اس لیے ایسی نادر صورت کے لیے منصوص حرمت میں استثنا پیدا کرنا درست نہیں ہے۔
۲۔ میں نے سر پر لگائی جانے والی جھلی، مصنوعی دانت اور ناخن پالش کے ساتھ وضو اور غسل کو درست قرار دیا ہے (ص ۲۲) جبکہ اہلِ علم کی رائے بالعموم اس کے برعکس ہے۔ میں نے جواز کی رائے اس اصول پر اختیار کی کہ شریعت کے مامورات میں حتی الامکان آسانی اور سہولت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ ان چیزوں کو وضو اور غسل سے مانع قرار دینے والے علما کی رائے زیادہ مبنی بر احتیاط ہے۔
۳۔ ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز کے حوالے سے میں نے لکھا تھا کہ اگر قیام کرنے اور قبلہ رخ ہونے کا التزام کرنے میں دِقت ہو تو یہ شرائط ساقط ہو جائیں گی اور بیٹھ کر کسی بھی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہو گا (ص ۲۴)۔ لیکن استاذِ گرامی فرماتے ہیں کہ قیام اور استقبالِ قبلہ کے حکم میں فرق ہے۔ ایسی صورت میں نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو تو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن قبلہ رخ ہونے کا التزام بہرحال کرنا ہو گا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ریل گاڑی پھر گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف رخ کر لے (بہشتی زیور ج ۲ ص ۵۰)۔
۴۔ بعض مسائل میں پوری تفصیل بیان نہ ہونے کی وجہ سے، فی الواقع، ابہام پیدا ہوا۔ یہ مسائل حسبِ ذیل ہیں:
میں نے لکھا تھا کہ چونکہ حکومتِ سعودیہ کی طرف سے حاجیوں کو مخصوص دنوں کا ویزا جاری کیا جاتا ہے اور ان کی واپسی کی تاریخ کئی دن پہلے مقرر ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر ایامِ حج میں عورت کو حیض آجائے تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہی طوافِ زیارت کر سکتی ہے۔ البتہ یہ واضح نہیں کر سکا کہ یہ اجازت فقہا کے نزدیک مشروط ہے یعنی اس صورت میں عورت کو کفارے کے طور پر قربانی بھی ادا کرنی پڑے گی (ارشاد الساری، ملا علی قاریؒ ص ۲۳۵)
اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی مکتب میں معلّمہ یا طالبہ ہو اور اس کے حیض کے ایام آجائیں تو چونکہ زیادہ دن چھٹی کرنے سے تعلیمی سرگرمیوں میں حرج واقع ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے حالتِ حیض میں قرآن کریم پڑھنا جائز ہو گا۔ فقہا اس میں مزید یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ وہ پوری آیت بیک دفعہ پڑھنے کے بجائے ایک ایک کلمہ کی الگ الگ ادائیگی کرے (عالمگیری ج ۱ ص ۲۴)۔
۵۔ اسلامی فقہ کے قواعد کے تحت میں نے ’’الاصل فی الاشیاء الاباحۃ‘‘ (اشیا میں اصل اباحت ہے) کے قاعدہ کا بھی تذکرہ کیا اور اس کے تحت متعدد احکام کا استنباط کیا ہے۔ استاذِ گرامی نے اس مسئلے پر اپنی کتابوں ’’راہِ سنت‘‘ اور ’’بابِ جنت‘‘ میں مفصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ اہلِ علم کے نزدیک مسلّم نہیں۔ اس پوری بحث کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ استاذِ گرامی نے یہ بحث اصلاً اہلِ بدعت کے استدلال کے تناظر میں کی ہے جو اس قاعدے کا سہارا لے کر بدعات کا دروازہ چوپٹ کھول دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادات کے دائرے میں ’’الاصل الاباحۃ‘‘ کا نہیں بلکہ ’’کل محدثۃ ضلالۃ‘‘ کا اصول جاری ہوتا ہے، اس لیے اس تناظر میں ’’الاصل الاباحۃ‘‘ کے قاعدہ کی تردید بالکل درست ہے۔
البتہ اجتہادی امور کے دائرے میں اہلِ علم کے ایک گروہ نے استنباطِ احکام کے حوالے سے اس قاعدے کو معتبر تسلیم کیا ہے(۲)۔ امام رازیؒ نے قائلین و مانعین کے موقف میں یوں تطبیق دی ہے کہ:
ان الاصل فی المنافع الاذن و فی المضار المنع۔
’’جن امور میں منفعت ہو اُن میں اصل اباحت، اور جن میں ضرر ہو اُن میں اصل منع ہے(۲)۔
میں نے اپنی بحث میں جن امور پر اس قاعدے کا اطلاق کیا ہے وہ اسی نوعیت کے ہیں اور ان میں منفعت و مصلحت کا واضح طور پر موجود ہے۔
آخر میں، میں ایک مرتبہ پھر اس گزارش کا اعادہ کروں گا کہ میری تمام آرا کو ایک طالب علم کی آرا کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ علمی دنیا میں فہم و استنباط کا اختلاف سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس کے بغیر، غالباً، نفسِ علم کا تصور بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی صاحبِ علم میرے استدلال کی کسی بھی کمزوری پر مجھے متنبہ کریں گے تو میں ان کا تہہِ دل سے شکرگزار ہوں گا اور، غلطی واضح ہو جانے پر‘‘ مجھے اپنی کسی بھی رائے سے رجوع کرنے میں، ان شاء اللہ، ہرگز کوئی تامل نہیں ہو گا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔
حواشی
(۱) ائمہ احناف کے نزدیک سری و جہری دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت جائز نہیں ہے، تاہم متاخرین میں سے مولانا عبد الحئی لکھنویؒ، مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیریؒ، اور مولانا ظفر احمد صاحب عثمانیؒ کے نزدیک سری نمازوں میں قراءت خلف الامام جائز ہے۔
(۲) الاشباہ والنظائر لابن نجیم ۱ ص ۹۷ و ۹۸۔ الاشباہ والنظائر للسیوطی ج ۱ ص ۶۰ ۔ الموسوعۃ الفقہیہ، وزارۃ الاوقاف والشؤون الاسلامیۃ الکویت ج ۱ ص ۱۳۰
(۲) ارشاد الفحول للشوکانی ج ۱ص ۳۷۴
ماڈل دینی مدارس کے قیام کا سرکاری منصوبہ
ادارہ
حکومتِ پاکستان نے سرکاری سطح پر ’’ماڈل دینی مدارس‘‘ کے قیام کا فیصلہ کیا ہے اور ’’مدرسہ تعلیمی بورڈ‘‘ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے دینی مدارس کے تمام وفاقوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری اعلان کی تفصیلات، ملک کے معروف قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت کا ادارتی تبصرہ، اور دینی مدارس کے وفاقوں کا مشترکہ اعلان قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)
سرکاری اعلان کی تفصیلات
اسلام آباد (این این آئی) حکومت نے دینی مدارس کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے، انہیں مربوط و منظم کرنے، اور ملک میں دینی و عصری علوم کے لیے ماڈل مدارس یا دارالعلوم قائم کرنے کے لیے ایک بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اُن دینی مدارس کا سلیبس تیار کرے گا جس کے مطابق ملحقہ مدارس نہ صرف اسلامی تعلیم بلکہ بورڈ کے تجویز کردہ عصری علوم کی تعلیم بھی دیں گے۔ بورڈ ان دینی مدارس کے لیے نصاب اور امتحانی نظام تیار کرنے اور پروگراموں میں مدد دینے کے لیے فنڈ قائم کرے گا۔
ہفتہ کو صدرِ مملکت جنرل پرویز مشرف کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جسے ’’پاکستان مدرسہ تعلیم (ماڈل دینی مدارس کا قیام اور الحاق) بورڈ آرڈیننس ۲۰۰۱ء) کا نام دیا گیا ہے جس کا اطلاق ملک بھر میں ہو گا اور یہ وفاقی حکومت کی تجویز کردہ تاریخ کو نافذ العمل ہو گا، اور یہ تاریخی مختلف علاقوں میں مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔
اس آرڈیننس کے اجرا کے فورًا بعد وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کے ذریعے ’’پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ‘‘ بنائے گی جسے اس آرڈیننس کے تقاضوں پر عملدرآمد کے لیے منقولہ و غیر منقولہ جائیداد حاصل کرنے سمیت دیگر اختیارات حاصل ہوں گے۔ بورڈ کا ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں ہو گا اور بورڈ ضرورت پڑنے پر علاقائی دفاتر بھی قائم کر سکتا ہے۔
بورڈ کا چیئرمین ایک معروف ماہرِ تعلیم ہو گا جبکہ وائس چیئرمین وفاقی حکومت چیئرمین کے مشورے سے متعین کرے گی جو وفاق یا تنظیم یا رابطہ کا صدر یا ناظم ہو سکتا ہے۔ بورڈ کا سیکرٹری ایک ماہرِ تعلیم ہو گا جسے انتظامی امور کا بھی تجربہ ہو گا۔ اس کے ارکان میں سیکرٹری تعلیم، مذہبی امور اور سائنس و ٹیکنالوجی کے سیکرٹری یا ان کے نامزد نمائندے شامل ہوں گے۔ دیگر ارکان میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا چیئرمین یا ان کا نامزد نمائندہ، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے نامزد دو علماء جو کونسل کے ارکان ہوں یا رہے ہوں، کسی یونیورسٹی میں اسلامی تعلیمات کے محکمے کا سربراہ پروفیسر، چاروں صوبائی سیکرٹری تعلیم، وفاق کا ایک صدر یا ناظم، تنظیم کا ایک صدر یا ناظم، رابطہ کا ایک صدر یا ناظم، چیئرمین انٹر بورڈ کمیٹی، اور وزارتِ سائنس و ٹیکنالوجی کے دو نمائندے ارکان شامل ہوں گے۔ سرکاری رکن کے علاوہ بھی وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ بورڈ میں شامل ہو گا۔
کوئی ایسا شخص بورڈ کا رکن نہیں بن سکے گا جو اخلاقی جرائم میں سزا پا چکا ہو، یا سرکاری ملازمت سے برطرف ہوا ہو، یا اسے سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہو۔ کوئی ایسا شخص جو براہ راست یا بالواسطہ بے ضابطگی کا مرتکب ہوا ہو، یا اس نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو، بورڈ کا رکن نہیں بن سکے گا۔ کسی رکن کے خلاف شکایت پر بورڈ اسے صفائی کا موقع دے گا اور بعد ازاں فیصلے کے لیے سفارشات وفاقی حکومت کو بھجوائی جائیں گی اور وفاقی حکومت کا فیصلہ حتمی ہو گا۔
مذکورہ بورڈ اس آرڈیننس کے مقاصد پر عملدرآمد کے لیے مکمل اختیار کا حامل ہو گا۔ وفاق، تنظیم، اور رابطہ کی خودمختاری میں مداخلت کیے بغیر بورڈ کو اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ ماڈل مدرسہ یا ماڈل دارالعلوم قائم کرے، جہاں اسلامی تعلیم سب سے اہم عنصر ہو گی، تاہم عمومی تعلیمی نظام کے نصاب کی بھی تعلیم دی جائے گی۔ بورڈ نظریاتی کونسل کی سفارش پر مدارس کے الحاق کی منظوری دے گا۔ ماڈل دینی مدارس میں تعلیم کے لیے نصاب کی منظوری دے گا۔ ماڈل دینی مدارس اور دارالعلوم میں تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرے گا۔ مدارس کے الحاق کے لیے قواعد کی منظوری دے گا۔ عمومی نظامِ تعلیم اور مدارس کے درمیان پائی جانے والی خلیج کو پُر کرنے کے طریقے تجویز کرے گا۔ اور دینی مدارس اور عمومی تعلیمی پروگراموں کو بہتر بنانے کے لیے ان پر نظرثانی کرے گا۔ نظریاتی کونسل کی سفارشات پر دینی مدارس میں امتحانات کے لیے قواعد و ضوابط کی منظوری دے گا۔ افسران اور سٹاف متعین کرے گا۔ دینی مدارس اور ان کی تنظیموں کے درمیان بہتر رابطے اور تعاون کو فروغ دے گا۔ ڈگریوں، ڈپلوموں، سندوں اور سرٹیفکیٹس کے بارے میں امور کی منظوری دے گا۔ ماڈل دینی مدارس اور ماڈل دارالعلوموں میں نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ کا ذمہ دار ہو گا۔
بورڈ ان مدارس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان کا معائنہ کرے گا۔ سکالرشپس، میڈلز اور انعامات کے قواعد مرتب کرے گا۔ دینی مدارس کی لائبریریوں کو ترقی دے گا۔ سالانہ بجٹ منظور کے گا۔ دینی مدارس کے امور کے بارے میں حکومت کو سفارشات پیش کر سکے گا۔ امتحانات کے امیدواروں کے داخلہ کے لیے کم از کم شرائط مرتب کرے گا۔ بورڈ کے ماتحت عہدوں کی تخلیق یا تحلیل کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے لیے منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اور اثاثوں کو منظم اور ان کی خرید و فروخت کرے گا۔
بورڈ کسی بھی رکن یا افسر یا کمیٹی یا سب کمیٹی کو بھی اختیارات تفویض کر سکتا ہے۔ بورڈ اپنی طرف سے قائم کیے گئے یا الحاق شدہ دینی مدارس کی بہتری کے لیے ان کے خلاف شکایات سنے گا اور ان کا ازالہ کرے گا۔ بورڈ ماڈل دینی مدرسہ اور ماڈل دارالعلوموں کے معائنے کے لیے بھی افسر مقرر کر سکتا ہے۔
بورڈ کے اجلاس چیئرمین طلب کرے گا اور ان اجلاسوں میں چھ ماہ سے زائد وقفہ نہیں ہو گا۔ بورڈ کے فیصلے اکثریتی بنیاد پر ہوں گے اور ٹائی کی صورت میں چیئرمین ووٹ استعمال کرے گا۔ چیئرمین بورڈ کا پرنسپل ایگزیکٹو آفیسر ہو گا اور سے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔
بورڈ کا سیکرٹری کل وقتی وفاقی حکومت کا ملازم ہو گا۔ تعلیمی کونسل کے سیکرٹری کے طور پر بھی کام کرے گا۔ اجلاسوں کے فیصلے تیار کرے گا اور بورڈ کے رجسٹرار کے طور پر بھی کام کرے گا۔
بورڈ کی ایک اکیڈیمک کونسل ہو گی جس کا چیئرمین بورڈ کا چیئرمین ہو گا۔ اور ارکان میں تعلیم اور سائنس و ٹیکنالوجی کی وزارتوں کے نمائندے، وزارتِ مذہبی امور کے ڈائریکٹر جنرل ریسرچ، چیئرمین انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیٹی، دو علماء، ایک سائنس دان اور ایک ماہرِ تعلیم اس کونسل کے رکن ہوں گے۔ یہ کونسل بورڈ کی مشاورتی کمیٹی ہو گی اور سلیبس، تعلیمی و امتحانی نظام بورڈ کی منظوری کے لیے پیش کرے گی۔
کوئی بھی دینی مدرسہ یا دارالعلوم بورڈ سے الحاق کر سکتا ہے جبکہ بورڈ اپنے ماڈل دینی مدارس اور دارالعلوم بھی قائم کرے گا۔ بورڈ کے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق کوئی بھی مدرسہ یا دارالعلوم الحاق کی درخواست دے سکتا ہے اور اس سلسلے میں بورڈ کا فیصلہ حتمی ہو گا۔ بورڈ سے ملحقہ ہر دینی مدرسہ اور دارالعلوم اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دینے کا پابند ہو گا۔ اور اگر کوئی دینی مدرسہ یا دارالعلوم مجوزہ قواعد کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا الحاق ختم کیا جا سکتا ہے۔
بورڈ ’’پاکستان مدرسہ ایجوکیشن فنڈ‘‘ کے نام سے ایک فنڈ قائم کرے گا جس میں عطیات سے ہونے والی آمدنی کے علاوہ وفاقی و صوبائی حکومتوں اور دیگر اداروں سے ملنے والی گرانٹس ہوں گی۔ وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر یہ فنڈ کسی بین الاقوامی ادارے سے گرانٹ نہیں لے سکے گا۔ بورڈ کے فنڈز ماڈل دارالعلوم اور دینی مدارس یا الحاق شدہ اداروں کے پروگراموں پر خرچ ہوں گے۔
(روزنامہ نوائے وقت لاہور ۔ ۱۹ اگست ۲۰۰۱ء)
روزنامہ نوائے وقت کا اداریہ
وفاقی حکومت نے دینی مدارس کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے، انہیں مربوط و منظم کرنے، اور ملک میں دینی و عصری علوم کے لیے ماڈل مدارس یا دارالعلوم قائم کرنے کے لیے ایک بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اُن دینی مدارس کا سلیبس تیار کرے گا جس کے مطابق ملحقہ مدارس اسلامی تعلیم کے علاوہ بورڈ کے تجویز کردہ عصری علوم کی تعلیم بھی دیں گے۔
موجودہ حکومت نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد نظام کی تبدیلی کے نام پر کم و بیش ہر شعبے میں مداخلت کی ہے اور ابھی تک یہ اپنے کسی منصوبے کے بارے میں کامیابی کا دعوٰی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اختیارات کی ضلعی سطح پر تقسیم سے پہلے اس نے معیشت کو دستاویزی شکل دینے اور ہر شہری کو ٹیکسوں کے جال میں لانے کا منصوبہ بنایا۔ کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستیں بنانے کا آغاز کیا۔ معاشرے کو اسمگلنگ اور اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ عوام نے حکومت سے تعاون کیا مگر بعض نقائص اور مناسب ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے یہ اقدامات مثبت برگ و بار نہیں لا سکے جس سے مایوسی میں اضافہ ہوا اور بطور خاص قومی معیشت بحران کا شکار ہوئی۔ اب حکومت نے لشکرِ جھنگوی اور سپاہِ محمد پر پابندی اور دو فرقہ وارانہ جماعتوں کو وارننگ دینے کے ساتھ دینی مدارس کے تعلیمی نظام کو بہتر، مربوط اور منظم کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے اور اس مقصد کے لیے تعلیمی بورڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
دینی مدارس کی بہتری، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو عصری علوم سے بہرہ ور کرنے، اور ان مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ کو معاشرے میں کھپانے کے لیے کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں:
- ایوب خان نے اس مقصد کے لیے بعض اقدامات کیے لیکن کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی۔ اوقاف کی تشکیل کی وجہ سے یہ تاثر پختہ ہوا کہ حکومت دینی مدارس کو مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔
- یحیٰی خان کے دور میں نور خان نے ایک تعلیمی سلسلہ کا اعلان کیا جس میں دینی اداروں کو بھی قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بعض تجاویز پیش کی گئیں مگر یحیٰی حکومت کے خاتمے کے ساتھ اس پالیسی کی بساط لپیٹ دی گئی۔
- بھٹو سے دینی طبقہ ویسے ہی بدکتا تھا اس لیے بھٹو حکومت نے جب دینی مدارس میں اصلاحات کا اعلان کیا تو اسے ایوب خان کی پالیسی کا تسلسل قرار دیا گیا۔
- جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک بھی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے جناب عبد الواحد ہالے پوتہ اور ڈاکٹر ایس ایم زمان کی سربراہی میں سفارشات پیش کیں، ان میں سے بعض پر عملدرآمد بھی ہوا۔ دینی مدارس کو گرانٹس بھی دی گئیں اور زکوٰۃ فنڈز سے بھی بعض دینی مدارس مستفید ہوئے۔ لیکن ہر حکومت کی طرح ضیاء حکومت نے بھی مخصوص مدارس کو نوازنے اور ان سے وابستہ علماء اور دینی شخصیات کا سیاسی تعاون حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فنڈ ضائع ہوا، علماء اور دینی مدارس میں سیاست نے زور پکڑا، اور جنرل صاحب کا حلقہ نیابت وجود میں آیا۔ مگر دینی اور دنیوی مدارس میں نہ تو دوئی ختم ہو سکی، نہ دینی مدارس میں عصری علوم کی تدریس کا خاطر خواہ انتظام ہو سکا۔
اب موجودہ حکومت نے ایک بار پھر یہ بیڑا اٹھایا ہے اور دینی مدارس کے تعلیمی بورڈ قائم کرنے کا آرڈیننس اس وقت آیا ہے جب ایک سینئر امریکی افسر تھامس نے واضح کیا ہے کہ بش انتظامیہ پاکستان کو دہشت گرد یا ناکام ریاست قرار دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ اسلام آباد مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ چونکہ سیکرٹری خارجہ ان دنوں امریکہ میں ہیں، اس لیے امریکی افسر کے اس بیان کی اہمیت واضح ہے۔ تاہم چونکہ امریکہ بقول قائد اعظمؒ دورِ حاضر میں اسلام کی تجربہ گاہ پاکستان کے دینی مزاج اور عوام کے دل و جان میں بسی روحِ محمد ﷺ سے خائف ہے۔ اور وہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کو بنیاد پرست اور ان کے جذبۂ جہاد کو دہشت گردی قرار دے کر ان کے بدن سے روحِ محمد ﷺ نکالنے کے درپے ہے۔
کوئی بھی ذی شعور انسان اور صحیح العقیدہ مسلمان نہ تو دہشت گردی کی حمایت کر سکتا ہے اور نہ مذہبی دہشت گردی کو جہاد کا نام دینے کی حماقت کر سکتا ہے۔ لیکن اسے بنیاد بنا کر دینی مدارس، مذہبی اداروں اور جماعتوں، اور دین کے نام لیوا نوجوانوں کے خلاف کارروائی یا انہیں حکومتی کنٹرول میں لانے کا حق بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔
یہ احساس تو ہمیشہ رہا ہے کہ دینی اور دنیوی تعلیم کا دوہرا نظام ختم ہونا چاہیے اور دینی مدارس میں بھی عصری علوم اسی طرح پڑھائے جانے چاہئیں جس طرح عصری علوم کے اداروں میں دینیات اور اسلامی تعلیم لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ہمیشہ سراہا گیا ہے اور بعض روشن خیال علماء کرام نے اپنے طور پر ایسے دینی ادارے قائم بھی کیے ہیں جہاں درسِ نظامی کے ساتھ عصری علوم کی تدریس بھی ہو رہی ہے۔ ایوب دور میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور ضیاء دور میں اسلام آباد کی اسلامی یونیورسٹی اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی، اور موجودہ حکومت اگر اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے تو اس کا خیرمقدم کیا جائے گا۔
تاہم اگر امریکی دباؤ اور سیاست دانوں سے فارغ ہونے کے بعد ہر جمہوری تحریک میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے دینی مدارس کو بھی محکمہ اوقاف سے وابستہ درباروں، مساجد اور علماء کرام کی طرح حکومتی اثر میں لانا مقصود ہے تو کوئی بھی پاکستانی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔
اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کے لیے یکساں نصاب مرتب کر کے نافذ کیا جائے جو ہمارے دینی اور قومی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ قومی نظامِ تعلیم میں جدید اور قدیم، اور دینی اور دنیوی کی تفریق ختم کر کے تمام مدارس کی حیثیت تخصیص کے اداروں کی ہونی چاہیے۔ جہاں قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ، علومِ شریعہ وغیرہ میں بین الاقوامی معیار کے کورس کرائے جائیں۔ جبکہ ان مدارس کے طالب علموں میں عہدِ حاضر کے علوم و فنون سے واقفیت کا اہتمام بھی کیا جائے تاکہ یہ ذہین اور دین سے گہری وابستگی رکھنے والے طالب علم کنویں کے مینڈک بن کر تنگ نظری کا شکار نہ ہوں اور عصری علوم کے ذریعے جدید رجحانات اور دنیا جہان میں ہونے والی پیشرفت سے بخوبی آگاہ ہوں۔
یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ دینی مدارس کو تمام سہولتیں فراہم کر کے انہیں آزادی اور خودمختاری کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے اور حکومتِ وقت کو عمل دخل کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ کیونکہ مختلف حکومتوں کی سیاسی مداخلت نے ہمارے جدید تعلیمی نظام اور اداروں کا بیڑہ غرق کیا ہے، وہ دینی مدارس میں بھی کوئی بہتری نہیں لا سکتی۔ اگر حکومت واقعی دینی مدارس کو جدید تعلیمی اداروں کی سطح پر لا کر نہ صرف معاشرے میں دینی تعلیمات کا فروغ چاہتی ہے بلکہ تعصب و تنگ نظری کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے تو پھر یہ کام دینی جماعتوں، دینی مدارس اور علماء کرام کے مشورے اور خوشدلانہ تعاون سے ہونا چاہیے۔ اور بورڈ کی تدوین و تشکیل میں بھی صاحب بہادر ٹائپ وفاقی و صوبائی سیکرٹریوں کے بجائے ان لوگوں کو شامل کیا جائے جن کی دین اور دینی تعلیمات سے وابستگی اظہر من الشمس ہے، جو دینی مدارس کی ضرورتوں اور نظام سے واقفیت رکھتے ہیں اور کم از کم عملی مسلمان ضرور ہیں۔ پھر حکمرانوں کو بھی اپنے فکر و عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ واقعی عملی مسلمان ہیں اور واقعتاً ان کے پیشِ نظر دینی مدارس کی اصلاح ہے۔
جہاں تک ان مدارس کے خلاف امریکہ و یورپ کے اس پروپیگنڈے کا تعلق ہے کہ وہ دہشت گردی کی نرسریاں ہیں، یہ محض اسلام کے خلاف خبثِ باطن ہے۔ ان دینی مدارس میں قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دی جاتی اور اسلامی تعلیمات میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ کا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متعصبانہ رویہ ہے جو مسلمانوں کی نوجوان نسل میں دین سے وابستگی کو راسخ کر رہا ہے، اور امریکہ و یورپ میں اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، اسلامی سنٹر قائم ہو رہے ہیں اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں اسلامی شعائر کی پابندی بڑھ رہی ہے۔
جہاں تک اسلامی عقیدے اور جذبۂ جہاد کا تعلق ہے، اس سے کوئی مسلمان بھی لاتعلقی اختیار نہیں کر سکتا، خواہ جنرل پرویز مشرف جیسا لبرل مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ دین کی نرسریوں، دینی مدارس کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے انگریزی اقتدار میں بھی اسلام کو شدھی اور سنگھٹن جیسی تحریکوں کی نذر نہیں ہونے دیا، اور اب بھی وہ اسلامی تعلیمات کے گہوارے ہیں۔ ان کی تعمیر و ترقی اور مثبت معنی میں روشن خیالی کے لیے ہر ممکن اقدام ہونا چاہیے لیکن یہ اس انداز میں نہ ہو کہ ان دینی مدارس کو بھی محکمہ تعلیم کے سکولوں اور کالجوں کی طرح سیاست کا اکھاڑہ بنا کر رکھ دیا جائے اور وہاں جو تھوڑی بہت دینی تعلیم دی جا رہی ہے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔
اس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد جو ماڈل مدارس اور دارالعلوم وجود میں آئیں گے ان سے اندازہ ہو سکے گا کہ حکومت کے پیشِ نظر کیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی بھی اپنے اصل مقاصد اور حکمتِ عملی کے مطابق تنظیمِ نو ہونی چاہیے، اور ان سے متعلقہ علماء کرام سے مشاورت کے بعد نئے مدارس کا الحاق انہی جامعات سے ہو، جو اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی تھیں۔ عجلت میں کوئی قدم نہ اٹھایا جائے ورنہ ناکامی قدم چومے گی۔
(نوائے وقت، ۲۰ اگست ۲۰۰۱ء)
دینی مدارس کے وفاقوں کا مشترکہ اعلان
لاہور (نامہ نگار + اے این این) پاکستان بھر کے دینی مدارس کے پانچوں بورڈوں نے ’’ماڈل دینی مدارس‘‘ کے قیام اور دینی مدارس بورڈ آرڈیننس کو مسترد کر دیا ہے، اور اسے مدارس کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مختلف مکاتبِ فکر کے پانچوں وفاقوں میں سے کوئی وفاق، مدارس بورڈ یا ماڈل دینی مدارس کی اسکیم میں شریک نہیں ہو گا۔ اور متحدہ وفاق پاکستان سے ملحق ۱۰ ہزار ۸۰۰ سے زائد ملک کے دینی مدرسوں یا بورڈ کو اس اسکیم میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
صوبائی دارالحکومت میں پانچوں مکاتبِ فکر کے مدارس کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد مقامی ہوٹل میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ’’اتحادِ تنظیماتِ مدارسِ دینیہ پاکستان‘‘ کے رابطہ سیکرٹری مولانا محمد حنیف جالندھری نے فیصلوں کا اعلان کیا۔
پانچوں وفاق المدارس کے دینی بورڈ کے فیصلوں کے مطابق حکومتِ پاکستان کی جانب سے ماڈل دینی مدارس کے قیام، دینی بورڈ، یا کسی اور عنوان سے کیے گئے اقدام کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور نہ کسی اسکیم میں شرکت کی جائے گی، اور نہ مجوزہ نظام میں کسی قسم کا تعاون کیا جائے گا۔
پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم دینی مدارس اور جامعات کی آزادی و خودمختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ اگر حکومت نے کسی بھی اقدام، قانونی، انتظامی حکم نامے کے اجرا، یا دستوری ترمیم کے ذریعے ان اداروں کو بلاواسطہ یا بالواسطہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پوری طاقت سے اداروں کا تحفظ کیا جائے گا۔ دینی مدارس کا اصل سرمایہ توکل علی اللہ ہے۔ ہم حکومت کی کسی بھی مالی پیشکش کی وجہ سے اصل سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
شرکاء نے کہا کہ دینی مدارس سے وابستہ علماء یا فارغ التحصیل طلباء کا مقصد حصولِ روزگار نہیں اس لیے حکومت دینی مدارس و جامعات پر دینی مدارس بورڈ سے وابستہ ہونے کے لیے حصولِ روزگار کا لالچ نہ دے۔ حکومت پہلے میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز، کمپیوٹر سائنز اور کامرس کے اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو روزگار دے، جس میں وہ ناکام ہے۔ حکومت دینی مدارس کے فاضلین کو کہاں سے روزگار مہیا کرے گی؟ اس لیے ملک کے تمام دینی مدارس کے پانچوں بورڈوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ماڈل دینی مدارس اور دینی مدارس آرڈیننس جامعات کے خلاف سازش ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں کوئی بھی دینی مدرسہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، اور حکومت محض الزام تراشی بند کرے کیونکہ حکومت ایک بھی دینی مدرسے میں دہشت گردی کے ثبوت فراہم نہیں کر سکی۔ مولانا محمد حنیف جالندھری نے کہا کہ دینی مدارس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک میں دہشت گردی گزشتہ ۸ سال سے ہو رہی ہے جبکہ دینی مدارس ۱۹۴۷ء سے قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر جدید دینی تعلیم دینا چاہتی ہے تو نیا سسٹم لانے کے بجائے پہلے سے قائم پرائمری، مڈل، ہائی سکولوں اور کالجوں کے نصابِ تعلیم میں تبدیلی لائے۔ دینی مدرسوں نے تو پہلے سے جدید عصری تعلیم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور دینی مدارس میں سائنس، انگلش، ریاضی سمیت کمپیوٹر کلاسز جاری ہیں۔
حکومت کے ماڈل دینی مدارس کے قیام اور دینی مدارس بورڈ کو مسترد کرنے والے پاکستان بھر کے دینی مدارس کے پانچ بورڈوں کے اجلاس میں مفتی عبد القیوم ہزاروی، مولانا سلیم اللہ خان، مولانا محمد حنیف جالندھری، مولانا محمد یونس بٹ، سید ریاض حسین نجفی، مولانا فتح محمد، مولانا حافظ فضل الرحیم، مولانا محمد اعظم، مولانا محمد صدیق ہزاروی، محمد افضل حیدری، محمد یاسین ظفر، نصرت علی شاہانی نے شرکت کی۔
تعارفِ کتب
ادارہ
’’مسند الامام ابی حنیفۃؒ‘‘
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ ’’ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی‘‘ نے امامِ اعظم حضرت امام ابوحنیفہ قدس اللہ سرہ العزیز کی روایاتِ حدیث کا مجموعہ ’’مسند الامام ابی حنیفۃ للامام ابی نعیم الاصفہانی‘‘ شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے اور ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی کے ڈائریکٹر محترم ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے اس کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کرایا ہے کہ
’’امام ابوحنیفہؒ (م ۱۵۰ھ) بطور فقیہ بلکہ فقہی مکتبِ فکر کے بانی کی حیثیت سے تو معروف ہیں، ان کی ایک حیثیت محدث کی بھی تھی۔ ان کی مرویات متعدد محدثین نے مرتب کی ہیں اور کم و بیش پندرہ (مسانید الامام ابی حنیفہؒ‘‘ سے دنیائے علم متعارف ہے۔ ان سب مسانید کو امام خوارزمیؒ نے ’’جامع المسانید‘‘ کے نام سے مرتب کر دیا تھا۔
ماضی قریب کے ایک بالغ نظر عالم مولانا محمد علی صدیقی کاندھلویؒ نے اپنی تصنیف ’’امام اعظم اور علم الحدیث‘‘ میں ’’مسانید الامام ابی حنیفہؒ‘‘ کے ذکر کے بعد لکھا تھا ’’افسوس ہے کہ یہ سارا ذخیرہ آج آثارِ قدیمہ کی نذر ہے۔ اللہ کرے کوئی صاحبِ علم بزرگ اس علمی خدمت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔‘‘
ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی اسلام آباد نے الحمد للہ امام حافظ ابو نعیم اصفہانیؒ (م ۴۳۰ھ) کی مرتبہ ’’مسند امام ابی حنیفہؒ‘‘ پہلی بار (ڈاکٹر عبد الشہید نعمانی، ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سنٹر کراچی یونیورسٹی کی) تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع کی ہے۔ اس اہم کتاب کا واحد نسخہ مکتبہ احمد ثالث استانبول میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر عبد الشہید نعمانی نے یہ بلند پایہ علمی کام اپنے والد ماجد اور حدیث کے استاذ مولانا عبد الرشید نعمانی مرحوم کی راہنمائی میں انجام دیا ہے اور اس پر کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی سند کا مستحق قرار دیا ہے۔‘‘
محترم ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب کے اس تعارفی نوٹ کے بعد ہم اس سلسلے میں مزید کچھ عرض کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور ملک بھر کے علمی اداروں، مراکز اور شخصیات سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس عظیم علمی ورثہ اور ذخیرہ سے استفادہ کی طرف توجہ دیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت و تقسیم کا اہتمام فرمائیں۔
’’مسند الامام ابی حنیفۃ‘‘ عربی زبان میں پونے چھ سو کے قریب صفحات پر مشتمل ہے جس کی قیمت تین سو روپے ہے اور ادارۂ تحقیقاتِ اسلامی پوسٹ بکس ۱۰۳۵ اسلام آباد سے طلب کی جا سکتی ہے۔
امام محمدؒ کی ’’کتاب الکسب‘‘ کا اردو ترجمہ
امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مایہ ناز شاگرد اور حضرت امام شافعیؒ کے استاذ محترم حضرت امام محمد بن حسن شیبانیؒ کی تصانیف میں ’’کتاب الکسب‘‘ صنعت و حرفت اور کسبِ حلال کی اہمیت و ضرورت اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے ایک اہم کتاب ہے جس سے اہلِ علم ہمیشہ استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔
ایک عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی صاحبِ ذوق اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں تاکہ اردو دان طبقہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازیں حضرت مولانا ولی اللہ مظاہری صدیقی مہاجر مدنی کو کہ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ ’’کسبِ حلال اور راہِ اعتدال‘‘ کے عنوان سے پیش کیا ہے اور اس میں حاشیہ اور فوائد کے طور پر بہت سی قیمتی معلومات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ البتہ اصل کتاب اور حاشیہ و فوائد میں امتیاز کی کوئی واضح صورت اختیار نہیں فرمائی جس سے عام قاری کو الجھن ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ ایک قابلِ قدر کاوش ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی ضرورت ہے۔
چار سو کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل یہ مجلد کتاب مولانا محمد مدنی نے شائع کی ہے جو پاکستان میں مکتبہ سید احمد شہیدؒ، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور سے طلب کی جا سکتی ہے۔
’’آخری صلیبی جنگ‘‘
محترم جناب عبد الرشید ارشد آف جوہر آباد ہمارے ملک کے باہمت اور باذوق دانشور ہیں جو امتِ مسلمہ کے خلاف صہیونی سازشوں اور سیکولر لابیوں کی معاندانہ سرگرمیوں کی نشاندہی اور ان کے مضمرات و نقصانات سے اہلِ اسلام کو آگاہ کرنے کی مہم میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ ان کے متعدد کتابچے اور مضامین اس سلسلے میں منظر عام پر آ چکے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے ’’آخری صلیبی جنگ ۔ وثائقِ یہودیت کے علمی اور عملی پہلو‘‘ کے عنوان سے ایک کتاب دو جلدوں میں شائع کی ہے جس میں یہود و نصارٰی، ہنود اور کمیونسٹ حلقوں کی خلافِ اسلام سرگرمیوں اور موجودہ عالمی تناظر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بین الاقوامی سازشوں، بالخصوص سیکولرازم اور مغربی ثقافت کی ہمہ گیر یلغار کا جائزہ لیا ہے اور اہلِ علم کو ان کے تعاقب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلا حصہ ۱۹۲ صفحات اور دوسرا حصہ ۳۷۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ جبکہ دونوں کی مجموعی قیمت ۲۲۵ روپے ہے۔
ہمارے خیال میں دینی محاذ پر کام کرنے والے علماء کرام اور کارکنوں کو اسلام اور مغرب کی کشمکش کے موجودہ عالمی تناظر سے آگاہی اور دینی ذمہ داریوں سے باخبر ہونے کے لیے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب النور ٹرسٹ، جوہر پریس بلڈنگ، جوہر آباد سے طلب کی جا سکتی ہے۔
ماہنامہ ’’نور علیٰ نور‘‘ (خطیبِ دین و ملت نمبر)
مولانا عبد الرشید انصاری کی زیرادارت کراچی سے شائع ہونے والے ماہنامہ ’’نور علیٰ نور‘‘ نے خطیبِ اہلِ سنت حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات و خدمات اور دینی مساعی کے تذکرہ کے لیے ’’خطیبِ دین و ملت نمبر‘‘ کے عنوان سے ڈیڑھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل خصوصی نمبر کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے جس میں مختلف اصحابِ علم و دانش نے اپنے اپنے انداز میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی کی ملی و دینی خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔
اس خصوصی اشاعت کی قیمت ۵۰ روپے ہے اور اسے مسجد عائشہ صدیقہ، سیکٹر ۱۱ بی، نارتھ کراچی سے طلب کیا جا سکتا ہے۔
چند اہم اور مفید رسالے
ہمارے محترم دوست اقبال احمد خان صاحب ایک عرصہ تک عجمان (متحدہ عرب امارات) میں مقیم رہے ہیں اور مختلف دینی موضوعات پر ممتاز اربابِ علم کی نگارشات شائع کر کے تقسیم کرتے رہے ہیں، جن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کا رسالہ ’’درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ‘‘، حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کے حالات و خدمات پر جناب طالب ہاشمی کا رسالہ ’’حضرت ابو عبیدہؓ‘‘ اور مولانا محمد عبد المعبود کا رسالہ ’’مسواک کی فضیلت‘‘ بھی شامل ہیں۔ حاجی صاحب موصوف آج کل گوجرانوالہ میں مقیم ہیں اور ’’ابوعبیدہ ٹرسٹ‘‘ کے زیر اہتمام مختلف تعلیمی و تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
مذکورہ رسائل دس روپے کے ڈاک ٹکٹ بھجوا کر پوسٹ بکس ۲۵۰ گوجرانوالہ کے پتے سے طلب کیے جا سکتے ہیں۔
اکتوبر ۲۰۰۱ء
امریکی عزائم اور پاکستان کا کردار
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
بعد الحمد والصلوٰۃ- محترم بزرگو اور دوستو! اس وقت پوری دنیا میں ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کو نیویارک اور واشنگٹن میں ہونے والے حادثات اور ان میں ہزاروں جانوں کے ضائع ہو جانے کے بعد اس پر امریکہ کے ردِ عمل اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر بحث کا سلسلہ جاری ہے اور میں بھی اسی حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
نیویارک کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر اور واشنگٹن کے پینٹاگون سے اغوا شدہ طیاروں کے ٹکرانے سے جو عظیم جانی و مالی نقصان ہوا، اس سے سب لوگوں کو دکھ ہوا ہے لیکن امریکہ نے اس کی ذمہ داری عرب مجاہد اسامہ بن لادن پر ڈال کر اس کی آڑ میں افغانستان پر حملہ کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس سے صورتحال میں اور کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت سے امریکہ کا مطالبہ ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دے مگر طالبان حکومت کا موقف یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے، اس کے مطالبہ پر غور کیا جائے گا۔ محض شک یا الزام پر وہ ایک مجاہد کو، جو ان کا مہمان ہے، امریکہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی افغان علماء کی مجلس شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسامہ بن لادن اپنے طور پر افغانستان چھوڑ دیں مگر انہیں امریکہ یا کسی اور ملک کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طالبان حکومت کا یہ موقف بہت پرانا ہے اور اس سے پہلے بھی امارتِ اسلامی افغانستان کی حکومت کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ اسامہ بن لادن رضاکارانہ طور پر افغانستان سے چلے جائیں تو ان کی مرضی ہے مگر انہیں بطور ملزم کسی ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ افغان علماء کی مجلسِ شوریٰ نے یہی بات اب ذرا مختلف انداز میں کہی ہے اور اسی سے وقتی طور پر کشیدگی میں کسی حد تک کمی کے آثار پیدا ہوئے ہیں مگر امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے آج امریکی ایوان نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ مسئلہ صرف اسامہ کا نہیں بلکہ وہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر میں دہشت گردوں کے تمام مراکز کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔
امریکہ کے نزدیک عالمِ اسلام کی جہادی تحریکات دہشت گرد ہیں اور جب وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہی جہادی تحریکات ہوتی ہیں جو مراکش سے انڈونیشیا تک اور چیچنیا سے صومالیہ تک پھیلی ہوئی ہیں اور کشمیر، فلسطین، چیچنیا اور مورو سمیت مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو غاصب اور مسلط قوتوں سے نجات دلانے کے لیے عسکری جدوجہد کر رہی ہیں۔ امریکہ اور اس کے حواریوں کا کہنا ہے کہ ان سب دہشت گردوں نے افغانستان میں ٹریننگ حاصل کی ہے، اس لیے افغانستان کو تباہ کرنا امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا ہے اور اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھرپور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ہم پہلے ہی عرض کیا کرتے تھے کہ اسامہ بن لادن کا نام صرف بہانہ ہے، اصل مسئلہ جہادی تحریکات ہیں جو امریکہ اور اس کے حواری ممالک کے لیے ناقابلِ برداشت ہوتی جا رہی ہیں اور اب صدر بش نے صاف طور پر تمام جہادی تحریکات کے خاتمہ کو اپنا سب سے بڑا ہدف قرار دے کر ہمارے ان خدشات کی تصدیق کر دی ہے۔
مگر اس میں ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان پر حملے کے لیے ہمارے کندھے پر بندوق رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کی زمین اور فضا سے حملہ آور ہو کر امارتِ اسلامی افغانستان کی طالبان حکومت کو ختم کرنے کے درپے ہے اور مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے اربابِ اختیار امریکہ کو افغانستان پر حملہ کے لیے زمینی اور فضائی سہولتیں فراہم کرنا چاہتے ہیں اور اسے اسلام اور پاکستان کے مفاد کا تقاضا بتا رہے ہیں۔ صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جس طرح افغانستان پر حملہ کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کی پالیسی کا دفاع کیا ہے، وہ انتہائی حیران کن ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
صدر محترم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا حوالہ دیا کہ آنحضرتؐ نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کر کے کفار مکہ کے خلاف احد اور خندق کی جنگیں لڑی تھیں جبکہ اس کے بعد حدیبیہ میں کفارِ مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر کے خیبر میں یہودیوں سے جنگ جیتی تھی اس لیے یہ عین حکمت اور دانش کا تقاضا ہے اور سنتِ نبوی کی پیروی ہے۔ لیکن جنرل صاحب کا یہ استدلال درست نہیں ہے اس لیے کہ نبی اکرمؐ کے سامنے دونوں قومیں کافر تھیں اور دونوں دشمن تھے۔ ان سے بیک وقت لڑنے کے بجائے حضورؐ نے ایک وقت میں ایک دشمن سے صلح کرنے اور دوسرے دشمن کے خلاف جنگ لڑنے کی حکمتِ عملی اختیار فرمائی جو فی الواقع دانش مندی کی بات تھی لیکن یہاں ایک طرف امریکہ ہے جس کی مہربانیاں نصف صدی سے ہم بھگت رہے ہیں اور دوسری طرف طالبان کی اسلامی حکومت ہے جس کی باقی تمام باتوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے بھی یہ حقیقت ہے کہ کابل میں طالبان حکومت کا وجود ہی پاکستان کی شمال مغربی سرحد کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اس لیے اس صورتحال پر جناب نبی اکرمؐ کی مذکورہ حکمت عملی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اور اسے غلط فہمی یا دھوکہ کے عنوان سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔
اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم کا تاریخ کے اس عظیم واقعہ سے پتہ چلتا ہے جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی فوجیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھیں اور دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کے درپے تھے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسیحی سلطنت روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت معاویہؓ کو پیش کش کی تھی کہ حضرت علیؓ کے خلاف جنگ میں وہ ان کی مدد کر سکتا ہے مگر حضرت معاویہؓ نے اسے انتہائی سختی کے ساتھ رد کر دیا اور وہ جواب دیا جو اسلامی تاریخ کا روشن باب اور قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ انہوں نے قیصر روم کے نام اپنے خط میں لکھا تھا کہ:
’’میری حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ دو بھائیوں کی لڑائی ہے جس سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور اگر تم نے حضرت علیؓ کے خلاف فوج کشی کی تو تمہارے مقابلے میں حضرت علیؓ کے پرچم تلے سامنے آنے والا سب سے پہلا سپاہی معاویہؓ ہوگا‘‘
یہ اس کیفیت کی بات ہے جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ ایک دوسرے کے خلاف حالتِ جنگ میں تھے جبکہ ہماری طالبان کے ساتھ کوئی جنگ بھی نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے اسلام کی تعلیم یہی ہے جو حضرت معاویہؓ نے قیصرِ روم کے نام اپنے خط میں بیان فرمائی ہے۔
جنرل صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو حملے کی سہولتیں فراہم نہ کیں تو بھارت ایسا کر دے گا اور پھر امریکہ بھارت کے ساتھ ہو جائے گا جس سے ہمارے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ میرے نزدیک یہ انتہائی بھولپن ہے اور یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو امریکہ کو جانتا نہیں ہے۔ امریکہ کے بارے میں یہ توقع رکھنا خود فریبی ہے جس کا شکار ہم سے پہلے ہمارے عرب بھائی ہو چکے ہیں۔ ہمارے برادر عرب ملکوں نے اسی توقع اور امید پر امریکہ دوستی کا پرچم اٹھایا تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں امریکہ ان کا لحاظ کرے گا اور ان کے امریکہ کا ساتھی بننے سے اسرائیل اور عربوں کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیوں میں توازن قائم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ساری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنی فوجیں سعودی عرب اور کویت میں بٹھا رکھی ہیں اور پشت پناہی اسرائیل کی کر رہا ہے۔ وسائل عربوں کے استعمال کر رہا ہے اور تحفظ اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے اس لیے ہمارے مہربانوں کو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہئے کہ امریکہ پاکستان میں بیٹھ جائے گا تو بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی حمایت بھی کرے گا اور پاکستان میں اس کی موجودگی سے پاکستان کے کشمیر کاز کو کوئی فائدہ بھی پہنچے گا۔ پھر یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب امریکہ کے بقول وہ جہادی تحریکات کا خاتمہ کر دے گا، پاکستان کو افغانستان سے لڑا دے گا اور چین کے سر پر فوجیں بٹھا کر پاک چین تعلقات میں رخنہ پیدا کر دے گا تو پھر کون سا کشمیر کاز باقی رہ جائے گا جسے بچانے کی ہمارے حکمران فکر کر رہے ہیں؟ ’’کشمیر کاز‘‘ اگر ہے تو وہ مجاہدین کی قربانیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے ہزاروں شہداء کا خون دے کر اسے زندہ رکھا ہوا ہے ۔جب یہ مجاہدین اور ان کے گروپ ہی دہشت گرد قرار پا کر پاکستان کے ہاتھوں امریکی انتقام کا نشانہ بن جائیں گے تو ’’کشمیر کاز‘‘ کا وجود ہی کہاں باقی رہ جائے گا؟
صدر محترم کا ارشاد ہے کہ ہم امریکہ کو افغانستان کے خلاف سہولتیں فراہم کر کے اپنی ایٹمی تنصیبات اور میزائل پروگرام کا تحفظ کر سکیں گے مگر یہ بات بھی خود فریبی ہے اس لیے کہ ہماری عسکری صلاحیت میں اضافے اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ اب تک جو کچھ کہتا آ رہا ہے، اس کے پیش نظر ہم اس قدر فاصلے سے اپنی ایٹمی تنصیبات کو امریکی مداخلت سے محفوظ تصور نہیں کر رہے تو جب وہ گوادر، کوئٹہ اور پشاور میں آ بیٹھے گا تو پھر ایٹمی تنصیبات کے تحفظ کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس لیے ہم دیانت داری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایٹمی تنصیبات اور میزائل پروگرام کا تحفظ امریکہ کے ساتھ فاصلہ قائم رکھنے میں ہے، اسے اپنی داخلی حدود میں براجمان ہونے کا موقع دینے میں نہیں۔
جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ امریکہ کو سہولتیں دینے کی پالیسی سے ہمیں معیشت کو سنبھالا دینے میں مدد ملے گی اور ہمارے معاشی حالات سدھر جائیں گے۔ میں اس کے جواب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ان عرب ممالک سے دریافت کر لیجئے جن کے کندھے پر دس سال سے امریکہ سوار ہے اور اس نے وہاں اپنی فوجیں بٹھا رکھی ہیں کہ امریکہ بہادر کی تشریف آوری اور اس کی فوجوں کی آمد سے ان کی معیشت کو کتنا سہارا ملا ہے؟ ان میں سے سعودی عرب کی حالت آج یہ ہے کہ تیل کی دولت سے مالامال اس ملک کو اپنا بجٹ کا خسارا پورا کرنے کے لیے عمرہ جیسی عبادت کو بزنس کے حساب سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے اور قرضے لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے اس لیے ہمارے نزدیک یہ بات بھی خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے خلاف فوجی سہولتیں دینے سے پاکستان کی معیشت سدھرنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔
حضراتِ محترم ! میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اصل مقصد کو پہچانیں اور اس کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نزدیک امریکہ کے موجودہ عالمی کردار اور بھاگ دوڑ کے بنیادی مقاصد تین ہیں:
- ایک یہ کہ دنیا بھر کی جہادی تحریکات کو دہشت گردی کا نام دے کر سختی کے ساتھ کچل دیا جائے اور افغانستان کو اس تمام تر دہشت گردی کا سرچشمہ قرار دے کر طالبان حکومت کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ اپنی مرضی کی حکومت بٹھائی جائے۔
- دوسرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں فکری ہم آہنگی اور نظریاتی یگانگت کے فروغ کو وسطی ایشیا تک پھیلنے سے روکا جائے۔ ان اثرات کے وسیع ہونے کے امکانات کو سامنے رکھ کر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ خطہ اگر دوبارہ اکٹھا ہو گیا تو بہت بڑی قوت بنے گا اور اسے بھارتی حلقوں میں ’’مغل امپائر‘‘ کے زندہ ہونے سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور اسے روکنے پر امریکہ اور بھارت دونوں متفق ہیں جس کی واحد صورت پاکستان اور افغانستان کی دوستی کو توڑنا ہے اور امریکہ اسے توڑنے کے لیے پاکستان کو افغانستان کے خلاف حملوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔
- امریکہ کا تیسرا مقصد چین کے خلاف حصار قائم کرنا اور پاکستان میں بیٹھ کر پاک چین دوستی میں رخنے ڈالنا ہے تاکہ چین اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہیں اور امریکہ ان کے حوالے سے آسانی کے ساتھ من مانی کر سکے۔
ان حالات میں آپ خود سوچ لیں کہ جب خدانخواستہ پاکستان کے تعلقات چین اور افغانستان دونوں کے ساتھ خراب ہو جائیں گے اور مجاہدین کے گروپوں کو بھی دہشت گرد قرار دے کر خود پاکستان کے ہاتھوں گراؤنڈ کر دیا جائے گا تو خطے میں خود پاکستان کی حیثیت کیا رہ جائے گی اور کیا کل کوئی صاحب یہ کہنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جائیں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیں بہت ہمدردی ہے اور ہمیں ان کی فکر بہت زیادہ ہے لیکن خود پاکستان کی سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدس ہے اس لیے کشمیریوں کو بھول جائیے اور پاکستان کے وجود کا تحفظ کیجئے۔
محترم بزرگو اور دوستو! میں نے حالات کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس صورتحال کا جائزہ لیں۔ یہ اسلام کے مفاد کی بات ہے، پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے اور طالبان کی اسلامی حکومت کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی دینی جماعتوں نے اس سلسلے میں جو موقف اختیار کیا ہے، وہ بالکل درست اور ملک و ملت کے مفاد کا تقاضا ہے اس لیے سب دوستوں کو چاہئے کہ وہ اس موقف کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور دینی قوتوں کو مضبوط کریں کیونکہ اس وقت دین، ملک اور قوم کے تحفظ کا یہی ناگزیر تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔
اختلافِ رائے کے آداب
مولانا قاری محمد طیبؒ
کسی عالم سے فرض کیجئے کہ آپ کسی مسئلے میں مختلف ہو جائیں، یا دوسرا عالم آپ سے مختلف ہو جائے، تو مسئلے میں اختلاف کرنا تو جائز ہے جب اپنے کو دیانتًا علی التحقیق سمجھے، لیکن بے ادبی اور تمسخر کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے کیونکہ بے ادبی اور تمسخر کرنا دین کا نقصان ہے۔ اور اختلاف کرنا محبت ہے، یہ عین دین ہے۔ دین جائز ہے اور خلافِ دین جائز نہیں۔ اختلافِ رائے کا حق حاصل ہے حتٰی کہ اگر ذاتی رائے اور مشورہ ہو تو انبیاء علیہم السلام سے بھی آدمی رائے میں مختلف ہو سکتا ہے۔ احکام اور اوامر کا جہاں تک تعلق ہے، اختلاف اور رائے زنی جائز نہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:
’’کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب حکم آجائے اللہ اور رسولؐ کا تو پھر اس کے سامنے چوں چرا کی جائے۔‘‘
تو جہاں تک احکامِ دین کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما دیں تو تامل بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ قبول نہ کرے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے، تو آدمی نہ مانے تو اس پر کوئی الزام و ملامت نہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اختلافِ رائے اگر اہل اللہ اور علماء میں ہو جائے تو مضائقہ نہیں۔ لیکن بے ادبی یا تذلیل کسی حالت میں جائز نہ ہو گی، اس لیے کہ وہ بہرحال عالمِ دین ہے جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس کا مقام و منصب بطور نائبِ رسول کے ہے، اس کی عظمت واجب ہو گی۔ ہم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پچاسوں مسئلوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں، مگر ادنٰی درجے کی بے ادبی قلب میں امام شافعیؒ کی نہیں آتی۔ اور جیسا کہ امام ابوحنیفہؒ واجب التعظیم ہیں ویسے ہی امام شافعیؒ بھی۔ دونوں آفتاب و ماہتاب ہیں، دونوں سے نور اور برکت حاصل ہو رہی ہے، کسی طرح جائز نہیں کہ ادنٰی درجے کی گستاخی دل میں آجائے۔
گستاخی جہالت کی علامت ہے
گستاخی اور استہزا کرنا جہالت کی بھی علامت ہے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے جب قوم کو نصیحت کی اور فرمایا کہ فلاں مقتول زندہ ہو جائے گا اگر بقرہ (گائے) ذبح کر کے اس کا گوشت اس سے چھو دیا جائے۔ تو اس پر بنی اسرائیل کہتے ہیںٖ کہ ’’اتتخذنا ھزوا؟‘‘ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اس بات میں کیا تعلق ہے کہ گوشت سے مردے کو جلا دیا جائے۔ موسٰی علیہ السلام نے فرمایا ’’اعوذ باللہ ان اکون من الجاھلین‘‘ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی دل لگی اور تمسخر کرنا جاہلوں کا کام ہے، عالموں کو مناسب نہیں کہ تمسخر کریں اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو ایک ہے رائے کا اختلاف اور کسی عالم سے مسلک کا اختلاف، اور ایک ہے بے ادبی، بے ادبی کسی حالت میں جائز نہیں، اختلاف جائز ہے۔
حضرت مولانا تھانویؒ اور مولانا احمد رضا خانؒ
میں نے مولانا تھانویؒ کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت سی چیزوں میں اختلاف رکھتے تھے۔ قیام، عرس، میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا۔ مگر جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے ’’مولانا احمد رضا خان صاحب‘‘۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے شخص نے کہیں بغیر ’’مولانا‘‘ کے ’’احمد رضا خان‘‘ کہہ دیا۔ حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا: عالم تو ہیں، اگرچہ اختلافِ رائے ہے، تم منصب کی بے حرمتی کرتے ہو، یہ کس طرح جائز ہے؟ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہم خطا پر سمجھتے ہیں اور صحیح نہیں سمجھتے مگر ان کی توہین اور بے ادبی کرنے کا کیا مطلب؟ مولانا تھانویؒ نے ’’مولانا‘‘ نہ کہنے پر برا مانا۔ مولانا تھانویؒ اہلِ علم میں سے تھے، وہ تو نام بھی کسی کا آتا تو ادب ضروری سمجھتے تھے، چاہے بالکل معاند ہی کیوں نہ ہو، مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے۔
کفر کا فتوٰی لگانے والوں سے مولانا نانوتویؒ کا سلوک
میں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کہ دہلی میں قیام تھا۔ حضرت کے خدام میں سے چند مخصوص تلامذہ ساتھ تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن امروہیؒ، حاجی امیر شاہ خان صاحب مرحوم، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ مولانا احمد حسن صاحبؒ نے اپنے ہم جولیوں میں بیٹھ کر فرمایا کہ بھئی لال کنویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قراءت بہت اچھی ہے، کل صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو شیخ الہندؒ نے غصے میں آکر فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی بے غیرت، وہ ہمارے حضرت کی تکفیر کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اور بڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملے حضرت نانوتویؒ کے کان میں پہنچے، اگلے دن حضرت نانوتویؒ ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کی خاطر پہنچے۔ اس امام صاحب کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، سلام پھیرا، چونکہ یہ اجنبی تھے، نمازیوں نے دیکھا کہ ہیں تو علماء صورت۔ تو پوچھا کون ہیں؟ معلوم ہوا کہ مولانا محمد قاسمؒ ہیں اور وہ ان کے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ، اور یہ مولانا احمد حسن محدث امروہیؒ ان کے شاگرد ہیں۔ امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں رات دن ان کو کافر کہتا ہوں اور یہ نماز کے لیے میرے پاس آگئے۔ امام نے خود بڑھ کر مصافحہ کیا اور کہا کہ حضرت، میں آپ کی تکفیر کرتا تھا، میں آج شرمندہ ہوں، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی حالانکہ میں آپ کو کافر کہتا رہا۔
حضرت نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدر ہے اور زیادہ عزت دل میں بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو جو روایت پہنچی کہ میں توہینِ رسول کرتا ہوں تو آپ کی غیرتِ ایمانی کا یہی تقاضا تھا۔ ہاں البتہ شکایت اس کی ہے کہ روایت کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی غیرتِ ایمانی کی قدر ہے، ہاں شکایت اس لیے ہے کہ ایک بار تحقیق کر لیتے کہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنٰی درجے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے ہاتھ پر ابھی اسلام قبول کرتا ہوں، اشھد ان لا الہ الا اللہ، اب امام بے چارہ قدموں میں گر پڑا، بچھا جاتا ہے۔
تو بات صرف یہ تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں تواضع للہ اور ادب مع اللہ اس درجہ رچا ہوا تھا کہ نفسانیت کا شائبہ نہ رہا تھا۔ استہزا اور تمسخر بجائے خود غلط ہے۔ اپنے معاندوں کی بھی بے قدری نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح محمل پر اتار کر یہ کہتے کہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں یہ ان کی قوتِ ایمانی کی دلیل ہے، البتہ یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعہ میں ہم توہینِ رسول کرتے ہیں؟ ہم معاذ اللہ دشمنانِ رسول ہیں یا دوستانِ رسول؟ اس کی تحقیق ان کو واجب تھی، بلا تحقیق حکم نہیں لگانا چاہیے۔
تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب اور تادّب دین کی بنیاد ہے جس کو عارف رومی نے کہا ہے:
از خدا خواہیم توفیقِ ادب
بے ادب محروم گشت از فضلِ رب
حق تعالٰی شانہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں جو گستاخ اور بے ادب ہے۔ اس زمانے میں چونکہ بے ادبی اور گستاخی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں، فرقہ بندی زیادہ ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے حق میں زبانِ طعن و ملامت اور زبانِ تضحیک کھولنا بہت معمولی بات بن گئی ہے، اس واسطے میں نے یہ سمع خراشی آپ لوگوں کی کی کہ اگر کسی عالم سے اختلاف آ بھی جائے تو اگر آپ خود عالم ہیں تب آپ پر فرض ہے کہ دوسرے کا احترام کریں۔ اور اگر آپ متّبع ہیں اور وہ اقتدا کر رہا ہے دوسرے عالم کی، تو عمل تو اپنے مقتدا و متبوع کی تحقیق پر کریں مگر دوسرے کے ساتھ تمسخر کرنا آپ کے حق میں بالکل جائز نہیں۔ بلکہ آپ یہ تاویل کریں کہ اس کے ہاتھ میں بھی حجت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو وہ کہتا ہے، عند اللہ وہ بھی مقبول ہے۔ ہر مجتہد خطا بھی کرتا ہے، اس پر عتاب اور عذاب بھیجنے لگیں تو یہ خدا کا مقابلہ ہو گا۔ حق تعالیٰ کے ہاں اجتہاد کی خطا پر بھی ملامت نہیں۔ آج کل فروعی اختلافات کی وجہ سے تمسخر بڑھ گیا ہے، یہ دین کے منافی ہے۔ بے شک آدمی عمل اپنی تحقیق پر کرے اور دوسرے کو معذور رکھے، ادب اور احترام میں کمی نہ آنے دے، یہ دانائی کی بات ہے۔
ائمہ مجتہدین کا باہمی طرزِ عمل
ائمہ مجتہدین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے ظاہری اختلاف رکھتے تھے لیکن ادب اور عظمت میں کمی نہیں کرتے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو امام (ابوحنیفہ) صاحبؒ کا مسلک ہے کہ نماز میں فاتحہ کے بعد آمین آہستہ کہنا، اور امام شافعیؒ کے ہاں زور سے کہنا افضل و اولٰی ہے۔ مگر جب امام شافعیؒ نے مزار والی مسجد میں نماز پڑھی تو آمین کو آہستہ سے پڑھا اور فرمایا، مجھے حیا آتی ہے اس صاحبِ مزار سے کہ اس کے قریب آ کر اس کے اجتہاد کے خلاف کروں۔ یہ ادب اور تادّب ہے یعنی جس حد تک گنجائش ہو۔ ایک تو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا فرق ہے کہ ایک کے ہاں جائز دوسرے کے ہاں حرام، اس میں تو دوسرے کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے، مگر جہاں اولٰی و غیر اولٰی کا فرق ہے وہاں ادب ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ امام شافعیؒ نے افضل پر عمل ترک اور غیر افضل پر عمل کیا امام صاحبؒ کی رعایت سے، حالانکہ امام ابوحنیفہؒ اس وقت مزار میں ہیں، سامنے نہیں ہیں مگر یہ ادب کا عالم تھا اور یہ ادب اور تادّب کی بات تھی۔
مسائل اور جذباتِ نفسانی
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلافات تھے۔ ائمہ مجتہدین میں اجتہادی مسائل پر جو اختلافات ہیں وہ صحابہ میں بھی تھے، لیکن باوجود اس کے اس ادب و احترام اور عظمت و تعظیم میں ذرہ برابر کمی نہ کی۔ اس لیے ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ مسائل کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہمارے نفسانی جذبات ہیں۔ ہم نے اپنے جذبات کو نکالنے میں مسائل کو آڑ بنا رکھا ہے۔ اگر یہ مسائل کی خاصیت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہؓ لڑتے کیونکہ ان کے ہاں بھی اختلاف تھا۔ اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے ہاں لاٹھی چلتی، پھر علماء ربانیین آپس میں لڑتے۔ مگر اختلاف بھی ہے اور ادب بھی۔ یہ دراصل اختلافِ رائے کے نام سے ہم اپنے جذبات نکالتے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ لڑنے کی چیز اصل میں جائیداد ہے، مکان ہے، جاگیر ہے۔ جب مسلمان کے پاس یہ چیزیں نہ رہیں، نہ جائیداد، نہ مکان، نہ سلطنت تو سوچا کہ بھئی دین کو لڑنے کا ذریعہ بناؤ اور مسائل کو آڑ بناؤ۔ تو یہ مسائل کی خاصیت نہیں۔ اختلاف کرنے کی گنجائش ہے مگر لڑنے جھگڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔
مسلمانوں کے فروعی اختلاف پر عیسائی جج کا طنز
ایک عرصہ پہلے ایک یورپین عیسائی کلکٹر تھا۔ اس کے زمانے میں احناف اور اہلِ حدیث میں لڑائی ہوئی ’’آمین‘‘ کہنے پر۔ حنفیوں نے آہستہ پڑھی، اہلِ حدیث نے زور سے کہی تو لاٹھی چل گئی، بہت سے لوگوں کا سر ٹوٹ گیا۔ مقدمہ کلکڑ کے ہاں گیا۔ فریقین کے وکلاء نے کلکٹر کو مقدمہ سمجھایا تو اس نے کہا کہ بھئی ’’آمین‘‘ کوئی جائیداد ہے یا بلڈنگ ہے کہ اس پر لڑتے ہیں؟ وکلاء نے کہا نہیں ’’آمین‘‘ ایک قول ہے جو زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی ہے کہ ’’آمین‘‘ زور سے کہو، دوسرے کہتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ آہستہ پڑھو۔ اس نے کہا جس کو جو حدیث معلوم ہے اس پر عمل کرے، لڑتے کیوں ہو؟ اور اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور سمجھ میں آنے والی بات بھی نہ تھی۔
بہرحال اس نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ لکھا کہ میں مقدمہ کی مثل دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں ’’آمین‘‘ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ’’آمین بالجہر‘‘ یعنی زور سے پڑھنا، ایک ’’آمین بالسّر‘‘ یعنی آہستہ پڑھنا، اور ایک ’’آمین بالشّر‘‘ یعنی جھگڑنے لڑنے کے لیے پڑھنا۔ لہٰذا میں دونوں کو سزا دیتا ہوں۔
گویا اس نے بتایا کہ اختلافی مسائل نہ لڑائی کے لیے ہوتے ہیں نہ باہمی نزاع کے لیے، وہ دیانتاً حجت سے رائے قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے قلوب کا فساد ہے کہ ہم نے مسائل کو اپنے دل کے جذبات نکالنے کی آڑ بنا لیا ہے اور ہر دین کا مسئلہ جھگڑا ڈالنے اور گروہ بندی کے لیے رہ گیا ہے۔
اختلافی مسائل میں راہِ صواب
اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو اسے بیان کرو مگر لڑنا کیوں ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا اور تم اپنی قبر میں جاؤ گے۔ کیونکر اس سے مسخرگی کرو؟ اور اسے کیا حق ہے کہ تمہارا استہزا کرے؟ آپ نے بیان کیا، امر بالمعروف کا حق ادا ہو گیا، اب اگر کوئی بات نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اگر اس کے پاس کوئی حجت ہے تو وہ عند اللہ جواب دے گا، تم ذمہ دار نہیں ہو، نہ تم سے آخرت میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر دین منوانا (یعنی اصولِ دین پر کسی کو مجبور کرنا) بھی ضروری نہیں، چہ جائیکہ فروعی اور اجتہادی مسائل کا منوانا ضروری ہو۔ بہرحال آج کل ذرا ذرا سے اختلافی مسائل پر لوگ نزاع کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس سے مسلمانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی قوت زائل ہو رہی ہے۔
ایک شخص اجتہادی رائے کے بارے میں اتنا جمود کرے کہ کسی کو معذور بھی نہ سمجھ سکے، یہ درحقیقت عوام کی اصلاح نہیں، فساد ہے۔ تو ایک چیز، چلّانے کی ضرورت نہیں کہ بار بار کہے۔ بس ہو گیا ایک مسئلہ کا اعلان، ماننے والے مانیں گے، تم ذمہ دار اور خدائی ٹھیکیدار نہیں ہو۔ ایک مسئلہ کا ضد اور اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہنا اور چباتے رہنا، اس سے خواہ مخواہ عوام میں نزاعات پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے والا تو بچ گیا اور مصیبت عوام پر آ گئی۔ ہاں ایک ہیں دین کے اصول، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، آپ زور سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن فروعی اور اجتہادی چیزوں میں آپ زور دیں تو یہ تبلیغی چیزیں ہی نہیں، آپ زور کہاں سے دیتے ہیں؟ مثلاً حنفی مسائل ہیں جو تبلیغی مذہب ہی نہیں۔ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہیں کہ لوگو، تم شافعی بن جاؤ، حنفی مت بنو۔ یہ ترجیحی مذاہب ہیں تبلیغی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں عمل واجب یا افضل ہے اور فلاں عمل نہیں۔ تو ترجیحی مذاہب کو تبلیغی مذہب مت بناؤ کہ اگر کسی عالم کی کوئی جزئی تحقیق ہو، خواہ مخواہ اس کی تبلیغ پر ضد اور اصرار کیا جائے۔
بہرحال آج کل یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، بہت گستاخی، جسارت اور جرأت ہو رہی ہے۔ اس واسطے یہ چند باتیں عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ اللھم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر۔
امریکہ میں دہشت گردی: محرکات، مقاصد اور اثرات
پروفیسر میاں انعام الرحمن
امریکہ میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں کون ملوث ہے؟ یہ واقعات کس کے ایما پر ہوئے؟ ان کے محرکات اور مقاصد کیا ہیں؟ اور ان واقعات سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جو آج کل تقریباً ہر ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، آئیے اس ضمن میں چند امکانات پر غور کریں۔ کیا یہ دہشت گردی اسامہ بن لادن اور مسلمانوں کی طرف سے کی گئی ہے؟ لیکن ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں:
- امریکی سکیورٹی کے فول پروف انتظامات میں سے حملے کے لیے ایک ہی ممکن راستے کو تلاش کر لینا مسلمانوں کے بس کی بات نہیں۔
- مسلم تاریخ سے تھوڑی سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی سول آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مسلم تاریخ کے مطالعہ سے مسلمانوں کی جو نفسیات (Psyche) ابھر کر سامنے آتی ہے، اس میں جنگ و جدل اور عسکریت کی موجودگی کے باوجود ایسے کسی رجحان کی علامت نہیں ملتی۔ ہمیں اعتراف ہے کہ اسلام میں جہاد اور عسکریت غالب عنصر کے طور پر موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی حدود و قیود بھی متعین ہیں۔ ایسے لوگ جو مغربی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر معذرت خواہانہ انداز سے اسلام میں عدمِ عسکریت تلاش کرتے ہیں اور دلائل و براہین کے ڈھیر لگاتے ہیں وہ اپنی فکری اپروچ میں ’’قادیانیت‘‘ کی سرحدوں کو چھو رہے ہیں۔
کیا حالیہ دہشت گردی میں جاپان ملوث ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسری عالمی جنگ کا بدلہ لینے کی کوشش کی ہو؟
عوامی سطح پر امریکہ مخالف جذبات کے باوجود جاپانی حکومت کی امریکہ نوازی سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ حملے کا خودکش انداز جاپانی انداز سے ملتا جلتا ہے لیکن ایک تو امریکہ اور جاپان میں مفادات کے حوالے سے کوئی تصادم نہیں، دوسرے جاپان کو اب بھی چین کو روکنے کے لیے امریکی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر جاپانی دوسری جنگ عظیم کے بعد عملاً فوجی برتری کی جانب راغب نہیں ہوئے۔
تو کیا حالیہ دہشت گردی میں چین ملوث ہے کیونکہ اس کے امریکہ سے تعلقات خاصے معاندانہ ہیں؟ نیز دہشت گردی جتنے منظم اور گہرے انداز سے کی گئی ہے وہ چینیوں کا خاصہ ہے۔
لیکن اس واقعہ کے بعد امریکہ نے جس تیزی سے ایشیا میں آنے کی کوشش کی ہے وہ اس مفروضے کے خلاف ایک ثبوت ہے کیونکہ یہ تصور کرنا درست نہ ہو گا کہ چینی قیادت امریکی ردعمل کا اندازہ نہ کر سکی ہو اور امریکہ کو اتحادیوں سمیت ’’چینی اثرات‘‘ کے علاقے میں اس طرح آنے اور قدم جمانے کا موقع دے۔ ویسے بھی ۱۹۴۹ء کے بعد چین کبھی ایسے واقعات میں ملوث نظر نہیں آیا۔ اس کے برخلاف امریکہ نے کئی بار چین کو جنگوں میں الجھانے کی کوشش کی لیکن چین کی مدبرانہ قیادت نے عسکری دوڑ اور جنگوں میں الجھنے کے بجائے معاشی ترقی کی طرف توجہ مبذول رکھی۔ مخصوص معروضی حالات میں چین کا یوں پینترا بدلنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ ویسے بھی چینی قوت کا اظہار و اثرات عالمگیر نہیں بلکہ علاقے تک محدود ہے۔
تو پھر اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم واقعی بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ
- دہشت گردی کے اس واقعہ سے کس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا؟
- اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو کسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا؟
اگر ہم ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیں تو مجرم تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس واقعہ کے مقاصد و محرکات کے ڈانڈے بہت دور رس اور عالمی سیاست سے علاقائی سیاست تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اکیسویں صدی فوجی برتری کے بجائے معاشی برتری کی صدی ہے۔ جو قوم یا ریاست اقتصادی امور پر چھائی رہے گی دنیا کی قیادت کرتی رہے گی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کے معاملات اگر اسی رفتار سے اور اسی نہج پر چلتے رہے تو کس قوم کو نقصان کا اندیشہ تھا؟
ماہرینِ معاشیات بتاتے ہیں کہ اگر دنیا کے حالات میں کوئی ڈرامائی تبدیلی نہ آئے تو اکیسویں صدی میں معاشی حوالے سے چین سب سے بڑی قوت ہو گا۔ ماہرین کے مطابق ۲۰۲۵ء تک دنیا کی Output کا ۲۵ فیصد چین سے ہو گا، جبکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ تقریباً موجودہ شرح ہی برقرار رکھ سکے گا جو تقریباً ۲۰ فیصد ہے۔ یورپی یونین کے ۱۵ ممالک جن کی موجودہ آبادی ۳۷۵ ملین ہے اور جن کا مشترکہ جی ڈی پی امریکہ سے تقریباً ایک ٹریلین ڈالر کم یعنی آٹھ ٹریلین ڈالر ہے، یہ اگلے پچیس سالوں میں تقریباً ۱.۵ کی اوسط سے بڑھے گا۔ اس طرح ۲۰۲۵ء تک یورپی یونین کا جی ڈی پی ۱۱.۴ ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ اور انڈیا کا جی ڈی پی بھی یورپی یونین کے جی ڈی پی کے لگ بھگ ہو گا۔ یورپی یونین میں متوقع توسیع کے پیشِ نظر ان کا جی ڈی پی ۲۰۲۵ء تک ۱۳ ٹریلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، اس طرح یورپی یونین واضح طور پر تیسری بڑی معاشی قوت کے طور پر ابھرے گا اور بھارت کا نمبر چوتھا ہو گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے جی ڈی پی کا ۸۵ فیصد سروس سیکٹر سے آئے گا جبکہ چین اور بھارت کے جی ڈی پی کا نصف زراعت اور مینوفیکچرنگ سے ہو گا۔
یہ تو تھی معاشی صورتحال، اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیسویں صدی میں چین سب سے بڑی معاشی طاقت ہو گا لہٰذا چین کا دائرہ کار بھی ’’علاقے‘‘ سے بڑھ کر عالمگیر ہو سکتا ہے، جس سے امریکہ کے مفادات بری طرح متاثر ہوں گے۔ نیز چین کی یہ برتری حادثاتی اور وقتی نہیں ہو گی بلکہ اس میں زراعت اور مینوفیکچرنگ کے پچاس فیصد کردار کی بدولت اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ جبکہ امریکہ کا سروس سیکٹر کسی بھی وقت بوجھ ثابت ہو سکتا ہے۔ چین اور امریکہ میں معاشی تفاوت ۲۰۲۵ء تک پانچ فیصد ہو گا جو کافی زیادہ ہے اور مزید بڑھ بھی سکتا ہے۔ امریکہ مختلف نسلوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگوں کی سرزمین ہے، ان میں باہمی رنجشیں بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ سرمایے کے ارتکاز بہت بڑھ جانے سے عوام کی اکثریت عدمِ تحفظ کے خوف کا شکار ہو سکتی ہے۔ ان کو دی گئی سہولتوں میں کمی ہو سکتی ہے جس سے امریکہ کو اندرونی طور پر سنگین مسائل پیش آ سکتے ہیں جس سے اس کی معاشی ترقی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ کا ہمسایہ وفاقی ملک کینیڈا اپنی اکائیوں کو مطمئن کرنے میں مصروف ہے، کینیڈین اثرات امریکہ کو مزید مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں۔
بین الاقوامی رائے عامہ بھی امریکہ مخالف ہو چکی ہے۔ قوموں کے معاملات میں امریکہ کی بے اصولی نے تقریباً ہر ملک میں، کم از کم عوامی سطح پر، شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ مسلم ورلڈ، چین اور اب عیسائی بھی امریکی برتری سے خائف ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح پر مساوات اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نسلی امتیاز کے خلاف ڈربن میں منعقد ہونے والی حالیہ کانفرنس میں امریکہ نے شرکت تک نہیں کی، لیکن بدلتا ہوا عالمی رویہ اکیسویں صدی میں نئے نظام کی نوید سنا رہا ہے جس سے امریکہ بجا طور پر خائف ہے۔
ابھی تک میں نے ہر جگہ لفظ ’’امریکہ‘‘ ہی استعمال کیا ہے اور چونکہ وہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے اس لیے تاثر عیسائی حکومت کا بنتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کے سیاسی و معاشی نظام میں یہودی کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکی پالیسیاں انہی کی مرضی سے بنتی ہیں۔ اگر امریکہ نے نسلی امتیاز کے خلاف کانفرنس میں شرکت نہیں کی تو یہ ’’برتر یہودی نسل‘‘ کے نظریے کا عملی اظہار ہے۔ ابھی تک امریکی پالیسی سازی میں بے پناہ اثرات رکھنے کے باوجود یہودی اب اس امر سے آشنا ہو چکے ہیں کہ امریکی عوام با خبر ہو چکے ہیں۔ اب امریکیوں کی اکثریت امریکہ سے یہودی اثرات ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ دنیا کے سمٹنے اور معلومات کی بھرمار کی وجہ سے تقریباً ہر قوم ذی شعور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ امریکی عوام کی رائے نہیں بلکہ یہودیوں کی بنائی ہوئی پالیسیاں ہیں۔ یہ بات یہودی جان چکے ہیں کہ مستقبل میں ان کے اثرات امریکہ میں کم سے کم ہوتے جائیں گے۔
پھر بین الاقوامی سطح پر مساوات اور برابری کی باتیں ہونے کی وجہ سے اقوامِ متحدہ کو بھی چند مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سے اہم سلامتی کونسل کے مستقل ممبروں کی ’’ویٹو پاور‘‘ ہے۔ اب دنیا کی قومیں اور عوام چاہتے ہیں کہ یہ چودھراہٹ ختم کی جائے۔ اس کے خاتمے کی ایک صورت اس کے ویٹو پاور رکھنے والے ممبروں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ صورت کوئی بھی ہو، چاہے ویٹو پاور کا مکمل خاتمہ ہو یا ویٹو پاور رکھنے والے ممبروں کی تعداد میں اضافہ، دونوں صورتوں میں امریکہ صرف ایک ریاست ہو گا جس کا صرف ایک ووٹ ہو گا۔ جبکہ بعض ایسے خطے جہاں یہودی اثرات موجود ہیں اور مزید جڑ پکڑ سکتے ہیں، وہاں ریاستوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لہٰذا اقوامِ متحدہ میں امریکہ کے بجائے کوئی ایسا خطہ ہی یہودی مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے تاکہ اقوامِ عالم ایک ریاست کی برتری کے غیر جمہوری رویے پر تنقید کرتے ہوئے یہودی مفادات کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔
ان حقائق کے ساتھ ساتھ حسبِ ذیل امور پیشِ نظر رکھیے:
- چونکہ ۲۰۲۵ء تک چین سپرپاور ہو گا اور امریکہ دو نمبر ہو گا، اندریں صورت یہودی سپرپاور چین کو استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اثرات چین میں مفقود ہیں۔ جبکہ نمبر دو طاقت یہودی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکے گی۔
- چین میں یہودی اثرات نہ ہونے کی وجہ اسرائیل بھارت تعلقات بھی ہیں۔ پچھلے دس سالوں میں ان تعلقات میں بہت تیزی آئی ہے۔ اور خطے میں بھارت چین کشمکش سے کون واقف نہیں؟
- نئے عالمی نظام میں چین کے سپرپاور بننے سے ’’بے اصولی‘‘ کو خاصا دھچکا لگے گا۔ سلامتی کونسل کے مستقل ممبروں کی ویٹوپاور تنقید کا نشانہ بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس تنقید کو کم کرنے کے لیے پہلے مرحلے پر یہ اصول اپنایا جائے کہ ویٹوپاور رکھنے والے پانچ رکن ممالک کی اکثریت سے ویٹو کیا جا سکے گا، یا پھر ویٹو کرنے کے لیے کم از کم دو ویٹو پاورز متفق ہوں۔ بہرحال موجودہ قواعد میں تبدیلی لانی پڑے گی۔
- اس طرح عالمی منظرنامے میں معاشی پہلو کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی امریکہ کمزور ہو جائے گا کیونکہ اس کا ایک ووٹ ہو گا جبکہ یورپی یونین کے دو ،اور اگر روس کو بھی شامل کر لیں تو تین۔
- اگر ویٹو پاور رکھنے والے ممبروں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو بھارت کو لازما شامل کیا جائے گا، بھارت کے اسرائیل سے دیرینہ مراسم ہیں۔
اس کے علاوہ ممبروں میں اکثریت یورپ سے لی جائے گی کیونکہ یورپ کے ممالک ہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔
اگر ہم درجِ بالا نکات کے بین السطور کو ذہن میں رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اب یہودی ’’شفٹ‘‘ کریں گے یعنی امریکہ کے بجائے یورپی یونین کو اپنے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں گے کیونکہ یورپی یونین کی سیاسی افادیت امریکہ کی نسبت بہت مؤثر ثابت ہو گی۔
اب سوال یہ ہے کہ اس اسکیم کے مطابق اکیسویں صدی کے لیے سیاسی طور پر تو یہودیوں کو ایک بڑا مضبوط پلیٹ فارم یورپی یونین کی صورت میں مل جائے گا لیکن یہودی معاشی امور پر کیسے کنٹرول حاصل کریں گے؟ کیونکہ ماہرینِ معاشیات کے مطابق معاشی میدان میں چین نمبر ایک، امریکہ نمبر دو، یورپی یونین نمبر تین، اور بھارت نمبر چار طاقتیں ہوں گی۔ امریکہ سے شفٹ ہونے کی صورت میں یہودیوں کے مفادات امریکہ سے وابستہ نہیں رہیں گے بلکہ امریکی عوام کی باخبری کی وجہ سے یہودی امریکہ مخالف ہو جائیں گے۔ اب یہودیوں کی کوشش ہو گی کہ ان کا نیا پلیٹ فارم یعنی یورپی یونین معاشی حوالے سے بھی ایک مؤثر اور نمبر ون پوزیشن اختیار کرے۔ یہودی ذہن کے مطابق اکیسویں صدی میں یورپی یونین کے لیے بھارت زرعی بنیاد کا کام دے گا۔ بھارت، اسرائیل اور یورپی یونین کے باہمی اتحاد سے نیا عالمی نظام قائم ہو گا جس کی ہیئت یہودی ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔
اب سوال یہ تھا کہ تیسرے اور چوتھے نمبر والی طاقتوں کو اوپر کیسے لایا جائے؟ اگر عالمی حالات اسی نہج پر چلتے رہتے تو چین نمبر ایک اور امریکہ نمبر دو ہوتے۔ اس طرح موجودہ حالات یہودیوں، ہندوؤں اور یورپی یونین کے مفادات کے خلاف تھے، اور موجودہ حالات میں کوئی تغیر برپا کر کے ہی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ امریکہ میں دہشت گردی کر کے اس ٹرائیکا نے درج ذیل مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے:
- امریکی معیشت پر ضرب اور امریکیوں میں عدم تحفظ کا احساس۔ اس واقعے کے بعد امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور امریکیوں میں باہمی عدم اعتماد جنم لے رہا ہے، پہلے سے موجود اندرونی اختلافات کو مزید ہوا دی جا سکتی ہے۔
- اس واقعے کے بعد امریکہ کا ایشیا کی طرف رخ کرنا۔ یہودیوں نے امریکی کارپردازوں کو مختلف آپشنز پر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کیونکہ تاحال یہودی امریکہ فیصلہ سازی میں بہت مؤثر ہیں۔ ایشیا میں امریکی آمد سے ٹرائیکا کے بہت سے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ایک تو اسلامی بنیاد پرستی کو روکنا، دوسرا سنٹرل ایشیا کی چھ مسلم ریاستوں اور افغانستان اور پاکستان کی ممکنہ ترقی کو لگام دینا، کیونکہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کر لینے سے ’’ایکو‘‘ کے پلیٹ فارم سے یہ ممالک حیرت انگیز تیزی سے اقتصادی ترقی کر سکتے تھے اور عالمی امور میں اجارہ داری کے خواہشمندوں کو سیاسی اور معاشی اعتبار سے چیلنج کر سکتے تھے۔ ایکو ممالک کی گہری قربت اور ترقی انڈیا کے مفاد کے بھی خلاف تھی۔
- امریکہ چین کو بھی کسی ملٹری ایڈونچر میں الجھانے کی کوشش کرے گا تاکہ چین اپنی معاشی پالیسی میں تسلسل قائم نہ رکھ سکے۔ ایسی صورت میں چین اور امریکہ دونوں کی معیشتیں موجودہ روش برقرار نہیں رکھ سکیں گی۔ علاقے میں انڈیا اور عالمی سطح پر یہودی اور یورپی یونین اس کے خواہشمند ہیں۔
- دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد حسب توقع امریکہ سے غیر ملکیوں بالخصوص اسلامی ممالک کے باشندوں کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ یہ لوگ واپس اپنے ممالک میں جا کر پہلے سے کمزور ممالک کے معاشی مسائل میں مزید اضافہ کریں گے۔
- اس کے علاوہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں عوامی سطح پر باہمی عدم اعتماد کا اظہار ہو گا۔ بین الاقوامی سطح پر اس ابتری سے یہودی سرمایہ کار بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔
- حالیہ امریکی بیانات سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ امریکی عزائم جز وقتی نہیں ہیں، امریکہ کا پروگرام طویل المیعاد ہے۔ امریکہ جتنا زیادہ عرصہ یہاں ٹھہرے گا اس کے چین سے تصادم کے امکانات اتنے ہی روشن ہیں، کوئی بھی واقعہ وجہ بن سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے دہشت گردی کرنے والوں نے اس حوالے سے کوئی منصوبہ تیار کر رکھا ہو۔ اگر امریکہ اور چین میں باقاعدہ تصادم نہیں بھی ہوتا پھر بھی دونوں ممالک ایک دوسرے پر نظر رکھنے میں مصروف ہوں گے اور اسی عمل کے دوران میں ان کے معاشی پروگرام ٹریک سے ہٹ جائیں گے۔
- زیادہ امکان یہی ہے کہ ایشیا بھی یورپی یونین کا ساتھ دے گا جس طرح اس نے دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔
اس سارے طویل المیعاد عمل کے دوران میں سب مغربی ممالک امریکہ کا ساتھ دیں گے اور امریکی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنے مخصوص مقاصد حاصل کریں گے بلکہ امریکہ کو بھی اس کے موجودہ مقام سے بہت پیچھے دھکیل دیں گے کیونکہ ان کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے۔
اگر ہم صورتحال کا ایک دوسرے زاویے سے جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ اگر عالمی حالات موجودہ روش کے مطابق چلتے رہتے تو مسلمانوں کو نقصان کا سامنا نہیں تھا، مسلم ممالک موجودہ ماحول ہی میں آہستہ آہستہ مؤثر اہمیت حاصل کرتے جا رہے تھے۔ لیکن دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد مسلم ممالک بالعموم اور پاکستان اور افغانستان بالخصوص سنگین صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو اس تغیر سے فائدہ اٹھانے والے مسلم ممالک نہیں ہیں اور افغانستان اور پاکستان تو بہت عجیب حالات کا شکار ہیں۔
اب اگر اس واقعہ سے فائدہ کے بجائے الٹا نقصان پہنچنے کا اندیشہ موجود ہے تو افغانستان، مسلم ممالک اور مسلمان ایسی دہشت گردی کیسے کر سکتے تھے؟ مسلمان اگرچہ زوال کا شکار ہیں لیکن ان کی سوجھ بوجھ اتنی بھی کم نہیں ہوئی کہ وہ ایسے کسی واقعے کے ردعمل کا اندازہ نہ کر سکتے، اور اپنا نقصان کرنے کے لیے ایسی دہشت گردی کے مرتکب ہوتے جو ان کے دین کے بھی منافی ہے۔
اب موجودہ صورتحال میں پاکستان کا موقف بہت ٹھیک ہے۔ اس ٹرائیکا نے یہ صورتحال پیدا کر کے پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی تھیں لیکن حکومتِ پاکستان مدبرانہ انداز سے اس کا جواب دے رہی ہے۔ دینی طبقوں کو چاہیے کہ حکومتِ پاکستان پر اندر سے دباؤ ڈالتے رہیں تاکہ حکومت اندرونی دباؤ کا اظہار کرتے ہوئے بہتر سودے بازی کی پوزیشن میں آ سکے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن ان حکومت مخالف جلسوں اور جلوسوں کے دوران بھارتی اور اسرائیلی ایجنسیوں کے ممکنہ اقدامات کو پیشِ نظر رکھا جائے، وہ علماء اور حکومت کے درمیان ’’حقیقی فاصلہ‘‘ قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا مدبرانہ انداز اختیار کرے، حکومتی موقف کے ساتھ ساتھ عوامی جذبات کو بھرپور کوریج دے تاکہ ہم ’’اندرونی پریشر‘‘ کو بھرپور انداز سے دکھا سکیں۔ سرمایہ دار، تاجر، صنعتکار اور زراعت سے وابستہ افراد اپنے کام میں لگے رہیں، کسی نام نہاد واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے سے خود کو محفوظ رکھیں، اس سے ملک بھی محفوظ اور مضبوط رہے گا۔ دانشور حضرات، اساتذہ اور طلبہ بھی مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے فکری پراگندگی کو پاس نہ پھٹکنے دیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ ٹرائیکا اپنے مقصد میں کامیاب جا رہا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے لیکن پاکستان نے کمالِ تدبر سے ان کے منصوبے میں ایک دراڑ ڈال دی ہے۔ پاکستان کا موقف ان کی امیدوں کے خلاف ہے۔ اگرچہ اس معمولی دراڑ سے ان کے منصوبے کی کلیت کو بہت زیادہ خطرات لاحق نہیں لیکن بین الاقوامی معاملات میں دلچسپی رکھنے والے ملٹری اسٹریٹجی میں سرپرائز سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سیاست کے مؤثر کردار اس ٹرائیکا کو ’’سرپرائز‘‘ دیں گے۔
پاکستانی معاشرے کی نئی دو قطبی تقسیم
ڈاکٹر اسرار احمد
امریکہ میں دہشت گردی سے پیدا شدہ تشویشناک ہی نہیں خوفناک عالمی صورتحال کے نتیجے میں جہاں افغانستان اور طالبان کے لیے شدید خطرات اور اندیشے پیدا ہو گئے ہیں، وہاں پاکستان بھی اپنی تاریخ کے مشکل ترین امتحان اور کٹھن آزمائش سے دوچار ہو گیا ہے، جس کے ضمن میں اختلافِ رائے میں شدت پیدا ہونے سے ملک کی سلامتی اور سالمیت تک کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
افغانستان کے لیے تو دشمن یہ تک کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دھات کے زمانے سے بھی پہلے کے دور یعنی پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، اور اگرچہ بائیس سالہ جنگ کے نتیجے میں افغانستان میں جس قدر تباہی و بربادی پہلے ہی آ چکی ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بے پناہ عسکری قوت کے پیشِ نظر بظاہرِ احوال بالفعل ایسا ہو جانا بعید از قیاس بھی نہیں ہے، تاہم یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ فی الواقع کیا ہو گا اور مشیتِ ایزدی کس طور سے ظاہر ہو گی، اور کیا عجب کہ اصحابِ فیل کا واقعہ دنیا میں ایک بار پھر ظاہر ہو جائے، واللہ اعلم۔ بقول علامہ اقبالؒ ؎
آج بھی جو براہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا
ادھر پاکستان میں ایک جانب حکومت اور اس کے ہم خیالوں اور دوسری جانب دینی و مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کے مابین اختلاف کی جو خلیج نمایاں طور پر سامنے آ چکی ہے، اس کے ضمن میں جہاں یہ اندیشہ ہے کہ ملک میں محاذ آرائی بڑھ کر تصادم کی صورت اختیار کر لے اور امن و امان کے درہم برہم ہونے کے نتیجے میں قومی سطح پر عدمِ استحکام کی صورت پیدا ہو جائے، وہاں اس اعتبار سے ایک بہت بڑا خیر بھی برآمد ہو رہا ہے کہ ملک میں ایک جانب سیکولر اور مغرب زدہ عناصر، اور دوسری جانب دین و مذہب کے ساتھ عملی و جذباتی تعلق رکھنے والے لوگوں کے مابین واضح امتیاز اور جداگانہ تشخص کا احساس و ادراک نمایاں طور پر پیدا ہو گیا ہے۔ گویا پاکستانی معاشرے میں ایک نئی دو قطبی تقسیم (Polarization) پیدا ہو رہی ہے جو پاکستان میں اسلامی انقلاب کے اعتبار سے نہایت مفید ہے۔
چنانچہ اس مرحلے پر حکومتِ پاکستان نے جو طرزِ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر جو احتجاجی جلسے منعقد ہو رہے ہیں یا جلوس نکل رہے ہیں ان سے وہ سیکولر اور مغرب پرست حلقے بالکل غائب ہیں جن کا فکر اور فلسفہ خالص مادیت کے گرد گھومتا ہے۔ لہٰذا ان کی ساری دلچسپی صرف حیاتِ دنیوی اور اس کے مادی اسباب و وسائل تک محدود، اور ساری تگ و دو اور بھاگ دوڑ دنیاوی سہولتوں اور آسائشوں اور بن پڑے تو تعیّشات کے حصول کے چکر میں رہتی ہے۔ اور احتجاج کُل کا کُل ان حلقوں کی جانب سے ہو رہا ہے جن کے نزدیک، خواہ عملاً اور خواہ صرف جذباتی طور پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے پر مقدم ہے۔ جن کا تعلق، خواہ فہم و شعور کے ساتھ، خواہ صرف عقیدے اور جذبے کی حد تک، دین و مذہب کے ساتھ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ان کے لیے تن من دھن قربان کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ اور جن کے نزدیک، خواہ شعوری یا بے شعوری طور پر، یہ حقیقت مسلّم ہے کہ ؎
دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملّت
ہے ایسی تجارت میں مسلماں کا خسارا
اب ظاہر ہے کہ صورتحال جیسے جیسے آگے بڑھے گی اور افغانستان اور طالبان کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کسی بالفعل اقدام میں حکومتِ پاکستان کے تعاون کے مظاہر منصۂ شہود پر آئیں گے، اس کے نتیجے میں پولرائزیشن میں مزید گہرائی و گیرائی اور سختی و پختگی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔
پاکستانی معاشرے کا یہ امتیاز و انقسام جہاں فی نفسہٖ مستقبل کے اسلامی انقلاب کے لیے نہایت مفید ہے، وہاں فوری طور پر ایک اور اعتبار سے بھی بہت مبارک ثابت ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے مختلف ہی نہیں متضاد قسم کے مذہبی عناصر کے مابین ازخود اور فطری طور پر اتحاد پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں اظہارِ اختلاف اور احتجاج کسی ایک خاص حلقے کی جانب سے نہیں بلکہ جملہ دینی حلقوں کی جانب سے ہو رہا ہے۔ گویا جملہ دینی عناصر اس معاملے میں رائے اور موقف کے اعتبار سے متحد اور یک زبان ہیں۔ خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، بریلوی ہوں یا دیوبندی، اہل سنت والجماعت ہوں خواہ اہل حدیث، اور خواہ قدیم طرز کے دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء ہوں یا جدید احیائی تحریکوں سے وابستہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ لوگ۔ اگرچہ ان جملہ عناصر پر مشتمل کوئی ’’گرینڈ الائنس‘‘ باضابطہ طور پر تاحال وجود میں نہیں آیا ہے اور اس وقت تک ’’دفاعِ افغانستان کونسل‘‘ میں، جو ۱۰ جنوری ۲۰۰۱ء کو وجود میں آئی تھی اور جس کا نام اب ’’دفاعِ پاکستان و افغانستان کونسل‘‘ ہے، ابھی تک عامۃ المسلمین کے سواد اعظم کے ان نامور اور نمایاں علماء و زعماء کی فعال شمولیت نظر نہیں آ رہی ہے جنہیں عرف عام میں بریلوی مکتب فکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تاہم اپنے طور پر جداگانہ انداز میں احتجاج میں وہ بھی بھرپور طور پر شریک ہیں بلکہ بعض مقامات پر تو انہوں نے اولیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ گویا یہ بات بالکل قرینِ قیاس ہے کہ جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھا، وقت کے تقاضے کے طور پر پاکستان کے جملہ دینی و مذہبی عناصر کا یہ گرینڈ الائنس وجود میں آجائے گا۔
اس پولرائزیشن کے دوسرے ’’قطب‘‘ (Pole) پر ’’قطب الاقطاب‘‘ کی حیثیت تو سربراہِ حکومت، سپہ سالارِ افواجِ پاکستان، پرستارِ اتاترک جنرل پرویز مشرف صاحب کو حاصل ہے۔ اور ان کے گرد رفتہ رفتہ پاکستانی معاشرے کے جملہ سیکولر عناصر جمع ہوتے جا رہے ہیں، خواہ پہلے ان کا تعلق دائیں بازو سے رہا ہو خواہ بائیں سے، اور خواہ وہ میدانِ سیاست کے کھلاڑی ہوں یا اربابِ دانش و اصحابِ قلم، اور خواہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کے حاضر یا ریٹائرڈ اکابر ہوں یا وہ جنہیں عرفِ عام میں تعلیم یافتہ سربرآوردہ طبقہ (Educated Elite) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کھلم کھلا ملحد اور دہریے ہیں، اور وہ بھی جو اسلام کو صرف ایک ’’مذہب‘‘ کے طور پر تو مانتے ہیں جو چند عقائد، چند عبادات اور چند معاشرتی رسوم تک محدود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اسلام کے ’’دینِ حق‘‘ یعنی نظامِ عدلِ اجتماعی کی حیثیت سے مکمل سیاسی، اقتصادی اور سماجی نظامِ حیات ہونے کے شعور سے عاری ہیں۔ گویا اس وقت پاکستان میں یہ دو نقطہ ہائے نظر بھرپور طور پر ممتاز و ممیز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر ایک جانب حکومتِ پاکستان ’’خاموش اکثریت‘‘ کی اپنی پسندیدہ جہت میں یکجہتی کے لیے کوشاں ہے تو دوسری جانب فعال دینی و مذہبی حلقے چاہتے ہیں کہ عوام ان کی جہت میں یکسو ہو جائیں۔
پاکستان میں تاحال دینی و مذہبی جماعتوں اور تحریکوں کی پیش قدمی میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی رہی ہے کہ اب تک ہمارے معاشرے میں یہ دونوں طبقے گڈمڈ رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اکثر و بیشتر سیاسی تحریکیں اسی ’’اجتماعِ ضدین‘‘ کی اساس پر چلتی رہی ہیں بلکہ سماجی تقریبات میں بھی یہ دونوں عناصر ’’من تو شدم تو من شدی‘‘ کا نقشہ پیش کرتے رہے ہیں۔ جبکہ اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام اور قوانینِ شریعت کے نفاذ، یا بالفاظِ دیگر اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے کہ پاکستانی معاشرے میں سورۂ آل عمران میں وارد شدہ الفاظِ مبارکہ ’’حتٰی یمیز الخبیث من الطیّب‘‘ کی کیفیت بالفعل رونما ہو جائے جس کے آثار اب بحمد اللہ نظر آ رہے ہیں۔
چنانچہ جمعہ ۲۱ ستمبر کی سہ پہر کو لاہور میں منعقد ہونے والا عظیم الشان جلسۂ عام اس حقیقت کا بہت بڑا مظہر تھا۔ اس لیے کہ اس کے سٹیج پر جہاں جملہ دینی عناصر کی نمائندگی اظہر من الشمس تھی وہاں معروف اربابِ سیاست کی غیر حاضری بھی بہت نمایاں تھی۔ حتٰی کہ اپوزیشن کے رہنما بھی کہیں نظر نہیں آئے جو عام حالات میں ہر وقت ایسے مواقع کی تلاش میں رہا کرتے ہیں کہ کسی بھی موضوع یا مسئلے پر حکومتِ وقت کے موقف کے خلاف جلسہ ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو کر خود اپنے لیے تقویت حاصل کریں۔ چنانچہ اس وقت کی احزابِ مخالف میں سے صرف ایک مسلم لیگ (ن) کے نوجوان رہنما سعد رفیق صاحب جلسے میں شریک ہوئے اور وہ بھی غالباً صرف اپنی ذاتی حیثیت میں شرکت کر رہے تھے۔ جماعتِ اسلامی کی مرکزی قیادت کی بھرپور موجودگی، جو کچھ عرصہ قبل طالبان کی زیادہ پرجوش حامی نہیں رہی تھی، بہت ہی نیک شگون ہے۔ چنانچہ میں قاضی حسین احمد صاحب کو اس پر تہِ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اگرچہ دو سوا دو سال قبل انہوں نے مجوزہ ’’متحدہ اسلامی انقلابی محاذ‘‘ میں شرکت سے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’ہمارا پختہ فیصلہ ہے کہ ہم آئندہ کسی بھی محاذ میں شامل نہیں ہوں گے‘‘ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ’’دفاعِ افغانستان کونسل‘‘ میں نہ صرف یہ کہ اول روز سے شرکت اختیار کی بلکہ اس میں مسلسل فعال رول ادا کر رہے ہیں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں دینی جماعتوں اور تنظیموں کا ایک وسیع تر اور منظم متحدہ محاذ قائم ہو جو نہ صرف امریکی جارحیت کی مخالفت کے منفی ہدف بلکہ پاکستان میں مکمل اسلامی انقلاب کے مثبت ہدف کے لیے مؤثر طور پر سرگرمِ عمل ہو، آمین یا رب العالمین۔
متعۃ الطلاق کے احکام و مسائل
محمد عمار خان ناصر
متعۃ یا متاع عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی بھی قسم کا فائدہ یا منفعت حاصل کی جا سکے، کل ما ینتفع بہ علی وجہ ما فھو متاع و متعۃ۔ اسلامی شریعت میں متعۃ الطلاق سے مراد وہ مالی فائدہ ہے جو طلاق یافتہ عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے تحفے کی صورت میں ملتا ہے۔ ذیل میں اس مسئلے کے بعض اہم پہلوؤں کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔
متعۃ الطلاق کی حکمت
حسنِ معاشرت کی بنیاد عقلِ عام اور دین کی رو سے ایثار و قربانی، اعلیٰ اخلاق اور تعاونِ باہمی کے جذبے پر ہے۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان زندگی کے تمام معاملات میں حسنِ اخلاق، مروت، رواداری اور شائستگی کا مظاہرہ کرے۔ حتٰی کہ معاملہ اگر تعلق توڑنے کا بھی ہو تو اسے بھی اس طرح عمدگی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا جائے کہ ناگزیر طور پر پیدا ہونے والی رنجشوں کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ یہی صورت نکاح کے معاملات میں ہے۔
قرآن مجید مرد کو اس کی فطری صلاحیتوں اور معاشی ذمہ داریوں کی بنا پر خاندان کا قوم اور سربراہ قرار دیتا ہے:
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضھم علیٰ بعض وبما انفقوا من اموالھم۔ (النساء ۳۴)
’’مرد اپنی بیویوں کے سربراہ ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں ان کی بیویوں پر فضیلت دی ہے اور وہ اپنے مال بھی (ان پر) خرچ کرتے ہیں۔‘‘
اس فضیلت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن مجید خانگی امور میں مرد کی رائے کو فیصلہ کن قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پہلو سے اس کو عورت پر ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے۔
وللرجال علیھن درجۃ (البقرہ ۲۲۸)
’’اور مردوں کو اپنی بیویوں پر ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے۔‘‘
لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ اپنے برتاؤ اور رویے میں بھی مردانگی اور بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ اور فتوت اور بلند کرداری کا یہ مظاہرہ قیامِ نکاح کی حالت میں ہی نہیں بلکہ اس صورت میں بھی ہونا چاہیے جب کسی وجہ سے رشتہ نکاح کا قائم رکھنا ممکن نہ رہے اور اسے توڑنے کی نوبت آجائے۔ چنانچہ قرآن مجید اس حالت میں تسریح باحسان اور مفارقۃ بالمعروف کی خاص طور سے تاکید کرتا ہے:
الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان (البقرہ ۲۲۹)
’’(رجعی) طلاق دینے کا حق دو دفعہ ہے۔ اس کے بعد یا تو دستور کے موافق بیوی کو رکھ لیا جائے یا خوش اسلوبی سے اسے چھوڑ دیا جائے۔‘‘
فامسکوھن بمعروف او فارقوھن بمعروف (اطلاق ۲)
’’اپنی بیویوں کو دستور کے موافق نکاح میں رکھو یا دستور ہی کے موافق ان کو جدا کرو۔‘‘
ہمارے نزدیک طلاق کی صورت میں عورت کو متعۃ دینے کا حکم بھی اس تسریح باحسان کی فرع ہے۔ قرآن مجید نے تسریح باحسان کے حکم کی جو تفصیل کی ہے وہ حسبِ ذیل ہے:
(۱) طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کو طویل تر کرنے اور اس کو تنگ کرنے کی غرض سے رجوع نہ کیا جائے:
ولا تمسکوھن ضرارًا لتعتدوا ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسہ (البقرہ ۲۳۱)
’’(طلاق کے بعد) اپنی بیویوں کو تنگ کرنے اور حد سے تجاوز کرنے کے لیے ان کو مت روکو، جو ایسا کرتا ہے یقیناً وہ اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھاتا ہے۔‘‘
(۲) مرد نے نکاح کے وقت یا اس کے بعد جو بھی مال عورت کو دیا ہے وہ واپس نہ لیا جائے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو:
وان اردتم استبدال زوج مکان زوج واٰتیتم احداھن قنطارًا فلا تاخذوا منہ شیئا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا وکیف تاخذونہ وقد افضٰی بعضکم الیٰ بعض واخذن منکم میثاقًا غلیظا (النساء ۲۰ و ۲۱)
’’اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور پہلے بیوی کو تم نے ڈھیروں مال دے رکھا ہے تو اب اس سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے مال واپس لیتے ہو؟ اور تم کیسے یہ مال واپس لے سکتے ہو جبکہ تمہارے ایک دوسرے سے ازدواجی تعلقات رہے ہیں، اور (نکاح کے وقت) تمہاری بیویوں نے تم سے (وفاداری کا) نہایت مضبوط پیمان لیا تھا۔‘‘
(۳) مہر کی ادائیگی میں مرد وسعتِ قلبی اور ایثار کا مظاہرہ کرے:
وان طلقتموھن من قبل ان تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضۃ فنصف ما فرضتم الّا ان یعفون او یعفوا الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب لتقوٰی ولا تنسوا الفضل بینکم (البقرہ ۲۳۷)
’’اور اگر تم اپنی بیویوں کو ہمبستری سے پہلے طلاق دے دو اور ان کے مہر کی مقدار تم نے طے کر رکھی ہو تو اب (طلاق کی صورت میں) انہیں طے شدہ مہر کا نصف ادا کرو۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں (تو تم سارا مہر رکھ سکتے ہو) یا اگر (خاوند) جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وسعتِ قلبی کا مظاہرہ کرے (تو عورت سارا مہر بھی لے سکتی ہے) اور تم شوہروں کا ایثار کرنا ہی تقوٰی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے اس کو فراموش نہ کرو۔‘‘
مولانا امین احسن اصلاحیؒ لکھتے ہیں:
’’قرآن نے مرد کو اکسایا ہے کہ اس کی فتوت اور مردانہ بلند حوصلگی اور اس کے درجے مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عورت سے اپنے حق کی دستبرداری کا خواہشمند نہ ہو بلکہ اس میدانِ ایثار میں خود آگے بڑھے۔ اس ایثار کے لیے قرآن نے یہاں مرد کو تین پہلوؤں سے ابھارا ہے۔ ایک تو یہ کہ مرد کو خدا نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ نکاح کی گرہ کو جس طرح باندھنے کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح اس کو کھولنے کا بھی مجاز ہے۔ دوسرا یہ کہ ایثار و قربانی، جو تقوٰی کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے، وہ جنسِ ضعیف کے مقابل میں جنسِ قوی کے شایانِ شان زیادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ مرد کو خدا نے اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے عورت پر جو ایک درجہ ترجیح کا بخشا ہے اور جس کے سبب سے اس کو عورت کا قوام اور سربراہ بنایا ہے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کو عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت مرد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس فضیلت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت سے لینے والا نہیں بلکہ اس کو دینے والا بنے۔‘‘(۲)
(۴) بیوہ عورت کی عدت اگرچہ چار ماہ دس دن ہے لیکن خاوند اگر قریب الوفاۃ ہو تو وہ اپنے اہلِ خانہ کو وصیت کر جائے کہ وہ اس کی وفات کے بعد ایک سال تک بیوہ کو اسی گھر میں رہنے دیں:
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجًا وصیۃ لازواجھم متاعًا الی الحول غیر اخراج (البقرہ ۲۴۰)
’’اور تم میں سے جو مرد قریب الوفات ہوں اور اپنے پیچھے بیوہ چھوڑ کر جا رہے ہوں تو وہ ان کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نکالے بغیر اسی گھر میں رہنے کی سہولت دی جائے۔‘‘
(۵) طلاق کی صورت میں عورت کی دلجوئی اور اس کے غم کو کم سے کم کرنے کے لیے خاوند مہر اور نفقہ کی لازمی ادائیگیوں کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی چیز بطور تحفہ عورت کو دے۔
وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا علی المتقین (البقرہ ۲۴۱)
’’اور اپنی مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کرو، یہ اہلِ تقوٰی پر لازم ہے۔‘‘
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتھا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحًا جمیلا (الاحزاب ۲۸)
’’اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی آسائشیں اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور اچھے طریقے سے تمہیں جدا کر دوں۔‘‘
متعۃ الطلاق کی قانونی حیثیت
طلاق یافتہ عورتوں کی چار حالتیں ہو سکتی ہیں:
ایک یہ کہ بوقتِ نکاح ان کا مہر مقرر کیا گیا ہو اور ہمبستری کے بعد ان کو طلاق دے دی جائے۔
دوسری یہ کہ مہر تو مقرر کیا گیا ہو لیکن ہمبستری سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے۔
تیسری یہ کہ مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور ہمبستری سے پہلے طلاق دے دی جائے۔
چوتھی یہ کہ مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور ہمبستری کے بعد طلاق دی جائے۔
ان مختلف صورتوں میں متعہ کی قانونی حیثیت کے بارے میں فقہاء کے مابین اختلافِ رائے ہے:
پہلی رائے امام حسن بصریؒ کی ہے جن کے نزدیک متعہ ان تمام مطلقات کے لیے واجب ہے۔ ان کا استدلال وللمطلقات متاع بالمعروف سے ہے جو تمام مطلقات کے لیے عام ہے۔
دوسری رائے احناف اور شوافع کی ہے جن کے نزدیک اس عورت کے لیے تو متعہ واجب ہے جسے دخول سے قبل طلاق دی گئی ہو اور اس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، لیکن باقی تمام مطلقات کے لیے محض مستحب ہے۔ ان کے دلائل حسبِ ذیل ہیں:
ایک یہ کہ قرآن مجید نے متعہ کا حکم خاص طور پر صرف اس مطلقہ کے لیے دیا ہے جس کا مہر طے نہ کیا گیا ہو اور دخول سے قبل اسے طلاق دے دی گئی ہو۔ ایسی عورتوں کے لیے یہ حکم قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے اور دونوں جگہ صیغہ امر متعوھن استعمال کیا گیا ہے جو کہ وجوب کی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوھن او تفرضوا لھن فریضۃ ومتعوھن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین (البقرہ ۲۳۶)
’’تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی ان بیویوں کو طلاق دو جن سے تم نے تعلقات قائم کیے ہیں نہ ان کا مہر مقرر کیا ہے، انہیں (رخصت کرتے ہوئے) کچھ دے دلا دو، خوشحال اپنی گنجائش کے مطابق اور تنگدست اپنی گنجائش کے مطابق، دستور کے مطابق کوئی تحفہ ہونا چاہیے جو احسان کرنے والوں پر لازم ہے۔‘‘
سورۃ الاحزاب میں فرمایا:
یا ایھا الذین امنوا اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموھن من قبل ان تمسوھن فما لکم علیھن من عدۃ تعتدونھا فمتعوھن وسرحوھن سراحا جمیلا (الاحزاب ۴۹)
’’اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تعلقات قائم کیے بغیر انہیں طلاق دے دو تو ایسی صورت میں ان کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، سو ان کو کچھ دے دلا دو اور شائستگی کے ساتھ ان کو رخصت کرو۔‘‘
دوسرے یہ کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ میں علی کا لفظ بھی الزام اور وجوب کے لیے ہے۔
تیسرے یہ کہ اس حکم کے آخر میں حقًا علی المحسنین کے الفاظ بھی وجوب کی دلیل ہیں۔
چوتھے یہ کہ عقل و قیاس بھی اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ شریعت کی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عقدِ نکاح میں عورت کو کوئی نہ کوئی مالی عوض ضرور ملنا چاہیے۔ چنانچہ نکاح کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم (النساء ۲۴)
’’ان عورتوں کے سوا باقی سب عورتوں سے مال دے کر نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔‘‘
چونکہ عقدِ نکاح کو قبول کر کے عورت خاوند کو استمتاع کا حق سونپ دیتی ہے اس لیے نفسِ نکاح کے ساتھ ہی عوض لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ عملاً خاوند نے استمتاع نہ کیا ہو، عوض کی ادائیگی اس پر لازم ہو جاتی ہے۔
مطلقات کی باقی تین صورتوں میں یہ عوض مہر کی صورت میں حسبِ ذیل تفصیل کے مطابق عورت کو ادا کیا جاتا ہے:
اگر عورت کو مہر مقرر ہونے اور دخول کے بعد طلاق دی گئی ہو تو اسے پورا مہر ملے گا۔
اگر مہر مقررہونے کے بعد اور دخول سے پہلے طلاق دی جائے تو اسے نصف مہر ملے گا۔
اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور دخول کے بعد طلاق دی جائے تو ازروئے حدیث عورت کو مہرِ مثل ملے گا۔
اس اصول کی رو سے ضروری ہے کہ وہ عورت جس کو مہر مقرر کیے بغیر دخول سے پہلے طلاق دی گئی ہو اسے بھی کوئی نہ کوئی عوض دیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایسی عورت کو متعہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ چونکہ ایسی عورت کے لیے دوسرا کوئی عوض نہیں ہے اس لیے اس کے لیے متعہ واجب ہے، جبکہ باقی مطلقات کو چونکہ مہر کا پورا یا کچھ حصہ مل جاتا ہے اس لیے ان کے حق میں متعہ صرف مستحب ہے۔(۳)
وللمطلقات متاع بالمعروف سے امام حسن بصریؒ کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے امام ابوبکر ابن العربیؒ اور امام جصاصؒ فرماتے ہیں کہ متاع کا لفظ عربی زبان میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ چنانچہ جن عورتوں کو پورا یا نصف مہر مل جاتا ہے ان کے لیے وہی متاع ہے اور جن عورتوں کو مہر نہیں ملتا ان کے لیے متاع کی صورت یہ ہے کہ خاوند اس کی دلجوئی کے لیے اس کو کوئی تحفہ پیش کرے۔(۴)
تیسری رائے امام مالکؒ کی ہے جو کہتے ہیں کہ متعہ کسی بھی مطلقہ کے لیے واجب نہیں بلکہ سب کے لیے مستحب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ومتعوھن کا حکم استحباب کے لیے ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حقًا علی المحسنین کا جملہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ متعہ کا یہ حکم قانونی طور پر نہیں بلکہ احسان اور تقوٰی کے لحاظ سے لازم ہے۔(۵)
مذکورہ قانونی بحث سے قطع نظر اتنی بات واضح ہے کہ قرآن مجید نے متعہ کا حکم نہایت تاکید اور اہتمام سے بیان فرمایا ہے، اور قانونی لحاظ سے نہ سہی لیکن اخلاقی لحاظ سے اس کا درجہ وجوب ہی کا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ حقًا علی المتقین کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
’’اوپر آیت ۲۳۶ میں مطلقہ عورتوں کو دے دلا کر رخصت کرنے کی جو ہدایت فرمائی تھی، آخر میں یہ پھر اس کی یاددہانی کر دی اور اس کو اہلِ تقوٰی پر ایک حق قرار دیا۔ جو حقوق صفات و کردار پر مبنی ہوتے ہیں بعض حالات میں وہ اس دنیوی زندگی میں تو قانون کی گرفت کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں لیکن خدا کے ہاں ان صفات کے لیے وہ حقوق ہی معیار ٹھہریں گے۔ اگر ایک چیز مومنین یا محسنین یا متقین پر حق قرار دی گئی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کا قانون اس دنیا میں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کوئی گرفت نہ کرے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آخرت میں بھی ان کی خلاف ورزی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہو گا، آخرت میں آدمی کا ایمان یا احسان یا تقوٰی انہی حقوق کی ادائیگی یا عدمِ ادائیگی کے اعتبار سے وزن دار یا بے وزن ٹھہرے گا۔‘‘(۶)
متعہ کی مقدار
متعہ کی مقدار کی تعیین میں اہلِ علم کے مختلف اقوال ہیں:
ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ متعہ کی مالیت کم از کم تیس درہم ہونی چاہیے۔
ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ متعہ کی اعلیٰ ترین صورت خادم ہے، اس کے بعد کپڑے اور اس کے بعد نفقہ۔
عطاءؒ فرماتے ہیں کہ درمیانے درجے کے متعہ میں قمیص، دوپٹہ اور چادر شامل ہونے چاہئیں۔
حسن بن علیؒ نے متعہ کے طور پر بیس ہزار اور شہد کے کچھ تھیلے اپنی مطلقہ کو دیے۔
قاضی شریحؒ نے متعہ کے طور پر پانچ سو درہم دیے۔(۷)
یہ تمام تعیینات اپنے اپنے محل میں درست ہیں کیونکہ قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ متعہ کی نوعیت اور مقدار کے باب میں کوئی چیز ازروئے شریعت متعین نہیں ہے بلکہ اس کا تعین مقامی رواج اور خاوند کے مالی حالات کے لحاظ سے کیا جائے گا۔
ومتعوھن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین (البقرہ ۲۳۶)
’’انہیں (رخصت کرتے ہوئے) کچھ دے دلا دو، خوشحال اپنی گنجائش کے مطابق اور
تنگدست اپنی گنجائش کے مطابق، دستور کے مطابق کوئی تحفہ ہونا چاہیے جو
احسان کرنے والوں پر لازم ہے۔‘‘
امام قرطبیؒ لکھتے ہیں:
وقال الحسن: یمتع کل بقدرہ، ھذا بخادم و ھذا با ثواب و ھذا بثوب وھذا بنفقۃ۔ وکذلک یقول مالک بن انس، وھو مقتضی القرآن فان اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یقدرھا ولا حدودھا وانما قال ’’علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ‘‘۔
’’حسن کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی گنجائش کے مطابق متعہ دے، کوئی خادم کی صورت میں، کوئی زیادہ کپڑوں کی صورت میں، کوئی ایک کپڑے کی صورت میں، اور کوئی نفقے کی صورت میں۔ امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں اور قرآن کا مدعا بھی یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار اور نوعیت متعین نہیں کی بلکہ فرمایا ہے کہ فراخ دست اور تنگ دست اپنی اپنی گنجائش کے مطابق دیں۔‘‘(۸)
حواشی
- راغب: المفردات فی غریب القرآن ص ۴۶۱ ۔ ابن الاثیر: النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ج ۴ ص ۲۹۳
- تدبرِ قرآن ج ۱ ص ۵۴۸
- ابن قدامہ: المغنی ج ۷ ص ۱۸۳ و ۱۸۴
- ابن العربی: احکام القرآن ج ۱ ص ۲۹۱ ۔ الجصاص: احکام القرآن ج ۱ ص ۵۸۳
- ابن رشد: بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۷۴
- تدبر قرآن ج ۱ ص ۵۵۶
- القرطبی: الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۰۱ و ۲۰۲ ۔ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم ج ۱ ص ۲۸۷ و ۲۸۸
- نفس المصدر ج ۳ ص ۲۰۱
پاکستان کے نظامِ حکومت میں خرابی کی چند وجوہات
ڈاکٹر زاہد عطا
یوں تو قیامِ پاکستان سے ہی اس مملکتِ خداداد کے نظامِ حکومت کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی ایک کمیشن نظامِ حکومت کے خدوخال طے کرنے کے لیے بنایا تھا لیکن بدقسمتی سے اس کمیشن کی اکثر سفارشات پر تو عمل نہ کیا گیا، صرف ایک سفارش یعنی غیر جماعتی انتخابات کو ۱۹۸۵ء میں اختیار کیا گیا، اور اسی غیر جماعتی اسمبلی نے فورًا جماعت سازی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلم لیگ (جونیجو) کے تحت منظم کر لیا جس سے اس سفارش کی بھی نفی ہو گئی۔
جنرل ضیاء کی وفات کے بعد چار انتخابات جماعتی بنیادوں پر منعقد ہو چکے ہیں لیکن ملکی حالات خواہ وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں یا سیاسی، پہلے سے بھی ابتر ہو چکے ہیں۔ عوام و خواص پریشان بلکہ مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ مسلم لیگ (ن) کو عوامی اکثریت کی حمایت حاصل رہی لیکن اکثر باشعور مسلم لیگی بھی یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ملکی حالات کو فورًا سدھارنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور فی الواقع وہ اپنے کسی بھی دورِ حکومت میں ملکی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ لا سکے۔
فرقہ اور مسلک کی بنیاد پر قائم مذہبی سیاسی پارٹیوں اور رہنماؤں میں بھی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو اس کرپٹ معاشرے اور نظام کو سیدھی راہ پر ڈال سکے۔ پاکستان میں اس وقت کچھ جماعتیں موجودہ نظام کے تحت ہی ملکی نظام کو چلانا چاہتی ہیں جن میں مسلم لیگ (ن) اور پیپلز پارٹی سرفہرست ہیں۔ کچھ چھوٹی علاقائی اور شخصی پارٹیاں مثلاً اے این پی، جمہوری پارٹی، ایم کیو ایم وغیرہ بھی جمہوری پارلیمانی نظام کے تحت ہی رہنا چاہتی ہیں۔
جماعت اسلامی جو پاکستان کی سب سے منظم جماعت ہے اور تربیت یافتہ کارکنوں کی ایک کثیر تعداد رکھتی ہے، ایک طرف مکمل اسلامی نظام کی داعی بھی ہے اور دوسری جانب موجودہ سسٹم کے تحت ہونے والے ہر الیکشن (سوائے ۱۹۹۷ء) میں حصہ بھی لیتی رہی ہے لیکن اپنی تنظیم، قربانیوں اور پاکستان اور اسلام کے ساتھ والہانہ لگن کے باوجود بادی النظر میں عوام کی اکثریت کو قائل نہیں کر سکی۔ ۲۴ جون ۱۹۹۶ء کو بے نظیر حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف ہونے والے مظاہرے اور پھر ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۶ء کے اسلام آباد دھرنے کے پروگرام سے لے کر اب تک جماعتِ اسلامی مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ موجودہ نظام کو بدلے بغیر اصلاح ناممکن ہے۔ قاضی حسین احمد کا یہ تجزیہ درست معلوم ہوتا ہے جس کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی موجودہ لیڈرشپ میں نہ صلاحیت ہے اور نہ ان کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی مملکت بنایا جائے۔
پاکستان میں آج کل لوگوں کی ایک خاصی بڑی تعداد یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت اصلاح کے فوری امکانات نہیں ہیں۔ جبکہ کچھ تنظیمیں اور ان کے سربراہ مثلاً دعوت و ارشاد کے حافظ محمد سعید، تنظیمِ اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر اسرار احمد، تنظیم الاخوان کے رہنما مولانا محمد اکرم اعوان، عوامی تحریک کے ڈاکٹر طاہر القادری جمہوریت اور جمہوری نظام کو بالکل غیر اسلامی قرار دیتے ہیں اور ان کی باتوں میں خاصا وزن بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچاس سال گزرنے کے بعد بھی اب تک ہم بحیثیت قوم کسی ایسے نظامِ حکومت کو اختیار کیوں نہیں کر سکے جو تسلسل سے جاری رہے؟ شاید پاکستانی عوام کے سماجی، معاشرتی، معاشی و مذہبی حالات و رجحانات کا پوری یکسوئی سے مطالعہ اور تجزیہ ہی نہ کیا گیا ہو۔
یوں تو یہ پولیٹیکل سائنس کے ماہرین کا کام ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو موجودہ کنفیوژن سے نکالنے کے لیے کوئی لائحہ عمل تجویز کریں، لیکن حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر باشعور پاکستانی اپنی استطاعت کے مطابق پاکستانی قوم کے مزاج، رویوں اور رجحانات کا بے لاگ تجزیہ کرے اور پھر اس کی روشنی میں پاکستان کے لیے موزوں ترین نظامِ حکومت کا خاکہ تجویز کرے۔
میرے خیال میں مندرجہ ذیل وجوہ ابھی تک موزوں نظامِ حکومت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں:
- قراردادِ مقاصد منظور ہو جانے کے بعد پاکستانی نظامِ حکومت کی بنیاد تو طے ہو گئی تھی یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکمِ مطلق ہے اور منتخب نمائندوں کو ایک مقدس امانت کے طور پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہو گا جو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے دائرے میں رہ کر ہی استعمال کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے کسی پاکستانی حکمران نے اس کو عملی صورت دینے کی مخلصانہ کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں جو صریحاً اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے خلاف ہیں، مثلاً سود اور سودی کاروبار۔
- دستورِ پاکستان میں پارلیمانی طرزِ جمہوریت کو اختیار کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن عملاً یہ ثابت ہوا ہے کہ پارلیمانی طرزِ جمہوریت پاکستانی عوام کے مزاج اور رجحانات کے مطابق نہیں۔ صدارتی جمہوریت جس میں صدر براہِ راست عوام کا منتخب کردہ ہو، پاکستانی عوام کے مزاج اور رویوں کے زیادہ قریب تر ہو سکتا ہے۔ ایسے تو قراردادِ مقاصد اور اسلام کے حوالے سے ’’جمہوری خلافت‘‘ کی اصطلاح زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔
- ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے، یہ ہے کہ اکثر پاکستانی (عوام و خواص) دوسروں کی خامیوں اور کوتاہیوں پر تو فورًا سیخ پا ہو جاتے ہیں لیکن اپنی خامی کسی کو نظر نہیں آتی، یعنی ساری قوم دوہرے معیارات چاہتی ہے۔ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ۔ بڑے سے بڑا دانشور، صوفی و پیر، مولوی و عالم، فوجی و سیاسی راہنما سبھی اس خرابی میں مبتلا ہیں۔ شاید ہی کوئی شخصیت ہو جس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ ظاہر و باطن کا یہی تضاد ہمارے اکثر مسائل اور مشکلات کی وجہ ہے اور یہی رویہ اسلام، دستور اور قرارداد مقاصد کے نفاذ میں بنیادی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
- ایک اور اہم رویہ جو کئی مسائل کو جنم دیتا ہے وہ ہے پاکستانی قوم کا جذباتی پن۔ جذبات میں آ کر ایسے ایسے مطالبے اور نعرے لگائے جاتے ہیں جن پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی آئیڈیلزم کا بھی شکار ہیں اور حقائق کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اسی آئیڈیلزم کا نتیجہ ہے کہ ایک جانب ہماری گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافتِ راشدہ کی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن دوسری جانب ہم اپنی ذرہ بھر اصلاح کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔
- زیادہ تر پاکستانی بے صبری کا بھی شکار ہیں، اس وجہ سے وہ تین سالوں میں ہی حکمرانوں اور نظام سے اکتا جاتے ہیں۔ اور یہ رویہ بھی نظام کے تسلسل میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ دستور میں ترمیم کر کے حکومت کا دورانیہ چار سال کر دیا جائے تو امید ہے کہ لوگ چار سال تک صبر کر لیں گے۔
- جو طبقے قوم کی راہنمائی اور تعمیر کر سکتے ہیں مثلاً اساتذہ، صحافی، ججز، مذہبی پیشوا (مولوی، پیر، مشائخ وغیرہ) اور سیاستدان، وہ خود بھلائی اور برائی میں تمیز کرنے سے قاصر ہیں، کجا کہ وہ افرادِ قوم کی تعمیر و اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ استاد، صحافی اور جج اپنے مقام سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ علماء اور پیر صاحبان اپنے مسلک اور فرقہ سے ہٹ کر کسی دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں۔ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے ملک و قوم کی ہر شے کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کجا کہ وہ ملک اور قوم کو صحیح نظامِ حکومت تجویز کرنے کا سوچ سکیں۔
- پاکستانی عوام کی اکثریت ناخواندہ ہے، اور جو خواندہ ہیں وہ بھی اپنے حقوق اور فرائض سے ناواقف ہیں۔ بلاشبہ پاکستانی عوام کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے لیکن بہت ہی قلیل لوگ ہوں گے جن کو اسلام کا صحیح شعور اور فہم ہے، اور اکثر لوگ اسلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مگر اپنی گفتگو میں زیادہ تر افراد یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ اسلام کا فہم کسی اور کو نہیں ہے۔ اسلام ایک فرد کو جو حقوق دیتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام جس طرح ہم سے مالی و جانی ایثار کا تقاضا کرتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اسلام کے مطابق ہمارا الٰہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس ہے، لیکن ہمارے عوام و خواص نے چھوٹے چھوٹے الٰہ بنا رکھے ہیں۔ کسی کا الٰہ اس کا افسر ہے تو کسی کا الٰہ اس کا جاگیردار ہے اور کسی کا الٰہ مولوی و پیر ہے۔ کسی کا الٰہ مال و دولت ہے تو کسی کا الٰہ حاکمِ وقت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت جرأت اور بہادری کا اظہار نہیں کرتی بلکہ معمولی چیزوں پر اپنا ایمان اور عزتِ نفس کا سودا کر لیتی ہے اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہر سطح پر مقتدر طبقوں کو من مانی اور ناانصافی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔
عام حالات میں بھی سچی اور کھری بات کم ہی لوگ کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر لوگوں کا وطیرہ یہ ہو گیا ہے کہ برے سے برے آدمی اور بری سے بری بات کو ٹوکتے بھی نہیں۔ اور جو سچی اور کھری بات کرتا ہے اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے پاکستانی اکثریت کے عمومی رویے میں خود غرضی کا اظہار ہوتا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ - پاکستان میں جاگیرداری نظام کی موجودگی بھی بے شمار خرابیوں کا باعث ہے۔ اکثر جاگیردار مذہبی خانقاہوں کے متولی بھی ہیں اور اب تو یہ لوگ سرمایہ دار بھی بن گئے ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دار طبقہ زمینیں خرید کر جاگیر دار بن گیا ہے۔ بیوروکریسی اور فوج کے اہم عہدوں پر انہی کے قریبی عزیز فائز ہوتے ہیں جو ہر حکومت میں ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ غیر ملکی آقاؤں (امریکہ و برطانیہ) کی پالیسیوں پر بھی انہی لوگوں کے ذریعے سے عمل کروایا جاتا ہے۔
میرے خیال میں یہی رویے اور وجوہات ہیں جو ایک قابلِ عمل نظامِ حکومت کو اپنانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ ’’نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن‘‘۔ ملک اور قوم کو اس پیچیدہ اور نازک صورتحال سے نکالنے کے لیے ایسا نظامِ حکومت اختیار کیا جانا چاہیے جو
- ایک جانب ہمارے عوام کی اخلاقی، تعلیمی، معاشی حالت کو پیشِ نظر رکھے اور ان کے نفسیاتی، معاشرتی اور مذہبی رویوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے۔
- دوسری جانب یہ نظام تعطل کا شکار نہ ہو بلکہ تسلسل سے چلتا رہے تاکہ پاکستان کو استحکام نصیب ہو اور قیامِ پاکستان کے مقاصد بھی پورے ہو سکیں۔
مولانا سعید احمد خانؒ ۔ چند یادیں
مولانا محمد عیسٰی منصوری
حضرت مولانا الیاسؒ کا طریقۂ دعوت
مولانا سعید احمد خانؒ کو مولانا الیاسؒ سے اس درجے کا تعلقِ خاطر اور محبت تھی کہ جب مولانا الیاسؒ کی تربیت، دعوت، حکمت کے واقعات سنانے لگتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ طوفان کا بند کھل گیا ہے جو اب بند نہیں ہو گا۔ اپنے خاص انداز میں گھنٹوں واقعات سناتے۔ اسی طرح حضرت مولانا الیاسؒ کے خاص الخاص خادم و رفیق میاں جی عبد الرحمٰن میواتی، جو نو مسلم اور مستجاب الدعوات تھے، کی دعوت و حکمت کے عجیب و غریب واقعات گھنٹوں تک سناتے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے میاں جی عبد الرحمٰن کو خاص حکمت عطا فرمائی تھی، ان کی روحانیت اور زبان کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم جامع مسجد دہلی سے بستی نظام الدین تک یکے (گھوڑا گاڑی) میں ساتھ بیٹھتا تو نظام الدین پہنچنے تک وہ مسلمان ہو چکا ہوتا، ان کے ہاتھ پر ہزارہا غیر مسلم دولتِ ایمان سے سرفراز ہوئے۔
فرمایا ایک بار ہم لوگ (مولانا الیاسؒ، میاں جی عبد الرحمٰنؒ اور مولانا سعید احمد خانؒ) میوات میں پیدل سفر کر کے کسی بستی میں جا رہے تھے، راستے میں کچھ میواتی بھی سفر کر رہے تھے، میاں جی نے ان میواتیوں کو آواز دی اور کہا، اے میوؤ، تم فاتحہ دلواؤ۔ اس دور کا میوات شرک و بدعات کی رسوم میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پوچھا، فاتحہ کون پڑھے؟ کہنے لگے ہمارا میاں (یعنی مکتبی مولوی) پڑھے۔ فرمایا، باپ دادا تو اس کے بھی مرے ہیں، کیا پتہ وہ چپکے سے اپنوں کو بخش دیتا ہو۔ پھر کہا گنجی (گڑ چاول کا خاص میواتی کھانا) تمہاری گئی اور ثواب اس نے اپنے باپ دادا کو بخش دیا۔ اس طرح پہلے انہیں شبہے میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا، یہ بتاؤ کھیر اس کا، دودھ گڑ چاول تمہارے یا میاں جی کے؟ کہنے لگے وہ تو سب ہمارے ہیں۔ فرمایا، جب دستر خوان پر میاں جی کا کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا بخشتا ہے؟ وہ تو تم بخشو (یعنی نیت کرو) جن کا ہے۔ سادہ دل میواتی کہنے لگے، سمجھ میں آگیا۔ اب ہم رسمی فاتحہ نہیں دلوائیں گے۔ پھر میاں جی عبد الرحمٰن نے مولانا سعید احمد خانؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم مولوی اگر ان سے بات کرتے تو کہتے بدعت ہے۔ اور وہ کہتا وہابی ہے، اور وہیں جھگڑا اور مناظرہ شروع ہو جاتا۔
مناظروں سے وحشت و تنفر
مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے، بھائی ہمیں حکمت اور لوگوں کو اپنا بنانا نہیں آتا۔ حضرت مولانا الیاسؒ کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت دی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاقِ عالیہ عطا فرمائے تھے جن کی بدولت وہ لوگوں کو اپنا بنا لیا کرتے تھے۔ مولانا الیاسؒ رسمی مناظروں کے سخت خلاف تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ان مناظروں سے اصلاح نہیں ہوتی، عناد بڑھتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ دعوت سے دل جڑتے ہیں اور مناظرے سے دل پھٹتے ہیں۔ فرمایا، مولانا الیاسؒ ایک بار کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دعوت دینی شروع کر دی۔ کسی نے آپ سے کان میں کہا یہ شخص تو شیعہ ہے۔ فرمایا کلمہ تو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے، یہ کہہ کر اس سے لپٹ گئے کہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ وہ شخص شیعوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا الیاسؒ کے طرز عمل سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ساری زندگی جب کوئی مولانا الیاسؒ کے متعلق پوچھتا تو وہ کہتے، وہ خدا کے خاص الخاص مقرب بندے ہیں، ہو سکے تو ان کی خدمت میں ضرور جاؤ۔ یہی حال مولانا سعید احمد خانؒ کا تھا، جو ایک بار آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا، ہمیشہ کے لیے آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔
حضرت مولانا سعید احمد خانؒ فرمایا کرتے تھے حق کے دلائل غیب کے ہیں جو ہر ایک کے جلدی سمجھ میں نہیں آنے کے، اور باطل کے دلائل مشاہدے کے ہیں جو عوام کو فورًا سمجھ میں آجاتے ہیں۔ اگر بات مناظروں تک ہی رہے تو عوام کے دلوں پر اہلِ باطل (اہلِ بدعات) کی بات ہی حاوی رہے گی۔ وہ تو حق کی محنت ہے جو باطل کو مٹا دے گی۔ غرض مولانا سعید احمد خانؒ نے برس ہا برس تک اس صدی کے سب سے بڑے داعی الی اللہ حضرت مولانا الیاسؒ کی صحبت اٹھائی۔ ان سے دعوت کی حکمت سیکھی اور ان کے فیضِ تربیت سے کندن بن کر نکلے۔ آپ پر دعوت کا ایسا رنگ چڑھا کہ زندگی کا مقصدِ وحید ہی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و طریقہ (دعوت و اتباعِ سنت) پر لانا بن گیا۔ اور آپ مولانا الیاسؒ کے دامن سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ’’من تو شدم تو من شدی‘‘ کے مصداق بن گئے۔
سادگی اور جفاکشی
حضرت مولانا سعید احمد خانؒ کو عیش و آسائش سے وحشت اور فقر و زہد سے رغبت تھی۔ سادگی اور زہد مولانا کی طبیعتِ ثانیہ بن گئی تھی۔ شروع زندگی میں اپنے گاؤں میں جو لباس، کھانا اور معاشرت تھی وہی آخر وقت تک برقرار رہی۔ وہی موٹا چھوٹا لباس، وہی سخت جوتا جو آپ کے گاؤں سے بن کر آتا تھا۔ مدینہ منورہ میں چند سال پہلے تک مولانا کی رہائش کچی مٹی کی بنی دیواروں کے سادہ سے مکان میں تھی۔ فرمایا کرتے تھے جسم کی بہت ساری بیماریاں جدید فیشن کی پختہ عمارتوں میں رہنے کی وجہ سے ہیں، مدینہ منورہ میں ہمارے گھر کی دیواریں مٹی کی ہیں اور تین چار فٹ چوڑی ہیں جو خودبخود سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رہتی ہیں۔ کھانا انتہائی سادہ تناول فرماتے، تنعم و آسائش کے نقشوں سے بہت ڈرتے اور اسے بڑا فتنہ سمجھتے۔ فرماتے دشمنانِ اسلام نے سازش کے تحت ہمیں سادگی اور جفاکشی سے ہٹا کر آرام طلب زندگی کا عادی بنا دیا ہے تاکہ ہم جہاد اور دین کی محنت کے قابل نہ رہیں۔
خوبصورت و عالی شان اور مزین مساجد میں جاتے تو ملول اور رنجیدہ رہتے۔ یہاں (انگلینڈ میں) لوٹن اور برمنگھم میں مرکز کی مساجد بننے سے پہلے عارضی طور پر نماز کے لیے سادہ سا ہال بنا دیا گیا تھا۔ مولانا ان سادہ سی مساجد کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ فرمایا، یہاں نماز میں خوب دل لگا ہے، کاش یہ مسجد ہمیشہ اسی طرح رہے، مگر تم لوگ ہماری بات کہاں مانو گے۔ بھارت کی ایک بستی میں لوگ دینی جامعہ کی شاندار عمارتیں دکھانے لے گئے، فرمایا تم میرے پاس مکہ مکرمہ آؤ، میں تمہیں اس سے بڑھ کر عالی شان عمارتیں دکھاؤں گا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ طلبا میں تقوٰی کتنا بنا ہے؟ اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو کتنے طلبا مدرسے میں رہیں گے؟ مولوی فاروق صاحب کراچی والوں کے یہاں دینی اجتماع اور پیٹ کے آپریشن کے سلسلے میں چند ہفتے رکنا پڑا تو خط لکھا جلدی سے بھاگ آؤ، جتنا کھا پی لیا وہی بہت ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں کی آسائش و راحت کے نقشے ہمارے آدمی کو بگاڑ نہ دیں۔
ایک بار ایک عرب ملک میں ایک ساتھی کا نرم و عمدہ بستر دیکھ کر فرمایا، آدھی بات امریکہ کی صحیح ہے، آدھی بات روس کی صحیح ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ سمجھ میں نہیں آیا، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مال دیا ہے وہ عیش کرنے کے لیے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مال و دولت کے خرچ کے لیے آٹھ مصارف بنا دیے کہ یہاں خرچ کرو۔ جب مسلمان نے مال و دولت کو اپنے کھانے، کپڑے، سواری اور رہائش کے اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے پر لگا دیا تو اس نے آٹھ لوگوں کا حق مارا۔ ان آٹھ کا ساتھی روس ہے کہ مال دار کا مال صرف اس کے عیش و راحت کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ روس کی یہی آدھی بات صحیح ہے۔ آگے جو روس کہتا ہے کہ مال دار کا پیٹ پھاڑ کر سر پھوڑ کر زبردستی چھین لو، اس کی یہ آدھی بات غلط ہے۔ امریکہ کی یہی آدھی بات صحیح ہے کہ زبردستی مال چھین کر لینے کا حق نہیں ہے۔ امریکہ کی دوسری آدھی بات غلط ہے کہ انسان کو جتنا مال ملے سب کو اپنے عیش و عشرت پر خرچ کرو۔ فرمایا، مسلمان کے مال کے خرچ کے غلط ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس پر دو عذاب مسلط کر دیے یعنی ایک کمیونزم اور دوسرے سرمایہ داری۔
علماء کی قدردانی و اکرام
آپ اہلِ علم اور طلبا کی بڑی قدر اور ان سے محبت فرماتے۔ ان سے ایسے گھل مل جاتے گویا گھر کے اصل لوگ یہی ہوں۔ مولانا کی خدمت میں تبلیغی کام کی نسبت سے جو علما پہنچتے ان سے بہت جلد بے تکلف ہو جاتے۔ اس کی کوشش فرماتے کہ ان کی علمی ترقی بھی ہو، مطالعہ و تحقیق کی عادت پڑے۔ جن علما کرام کو مطالعے کا عادی پاتے، ان کی خصوصی رعایت فرماتے، اور بسا اوقات ان سے علمی تحقیق کا کام بھی لیتے۔ عام طور پر سفر و حضر میں مولانا کے ساتھ کوئی ایسے عالم ضرور ہوتے جن کے ذمے مختلف احادیث و واقعات کی تخریج و جستجو و تلاش لگاتے، ان کی محنت پر خوب ہمت افزائی فرماتے، بعض اوقات خوش ہو کر انعام بھی دیتے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ قیام کے دوران حج و عمرہ کے لیے آئے ہوئے علما کی خصوصی دعوتیں کرتے۔ حج کے دنوں میں دعوت کا اہتمام عموماً جمعہ کے دن ہوتا۔ علما کے لیے کھانے اہتمام سے تیار کرواتے، کھانے کی مجلس علمی مذاکرے کی مجلس بن جاتی۔ صحابہ کرامؓ اور اکابر کے واقعات سناتے اور کوشش فرماتے کہ ان میں عوام پر دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہو۔ فرماتے کہ امام کا اپنے نمازیوں سے ایسا دلی تعلق ہونا چاہیے جیسا خاندان کے سربراہ کا اپنی آل و اولاد سے ہوتا ہے۔ صرف نماز پڑھا کر امام کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی بلکہ نمازیوں کی خبر گیری، بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، ان کے اپنی دنیاوی و معاشرتی مسائل کی فکر کرنا بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ ان مجالس میں علما بے تکلفی سے اشکالات پیش کرتے اور مولانا دلائل سے جواب مرحمت فرماتے۔
تواضع اور کسرِ نفسی
حضرت مولانا کی تواضع اور کسرِ نفسی کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی تنقید بھی قبول فرماتے۔ اس دور میں یہ چیز بالکل نایاب ہو گئی ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، لندن تبلیغی مرکز کے خصوصی کمرے میں بندہ ملاقات کے لیے پہنچا۔ دیکھا مولانا کی پاکستانی جماعت کے رفقا اور انگلینڈ کے متعدد اہلِ شورٰی تشریف فرما ہیں اور کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے۔ سنا تو پتہ چلا کہ کسی بیاض (کاپی) میں سے مبشرات پڑھے جا رہے ہیں۔ یعنی کسی جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، خواب میں حضرت مولاناؒ کو حضورؐ کے ہمراہ دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ چند منٹ بعد بندہ نے عرض کیا، حضرت! آپ کی مجلس میں اس طرح مبشرات سننا سنانا مناسب نہیں۔ آپ یہ مبشرات بعض بزرگوں کے لیے، خلفاء کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ بزرگ الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں چھاپ کر یہاں ہمیں ابتلا میں ڈالتے ہیں۔ سنا ہے حضرت مولانا الیاسؒ نے دعا مانگی تھی ’’اے اللہ! ہمارے اس کام کو مبشرات اور کرامات پر مت چلانا‘‘۔
یہ سننا تھا کہ اسی وقت حضرت مولانا نے بیاض بند کر دی۔ فرمایا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مبشرات سے دل کو تقویت پہنچتی ہے، مگر یہ پہلو بھی قابلِ لحاظ ہے بلکہ زیادہ اہم ہے، اس سے کئی فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے عمومی طور پر مبشرات کے سننے سنانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔
اسی طرح ایک بار انگلینڈ کے سالانہ اجتماع کے اختتام پر ڈیوزبری میں مختلف شہروں کی مساجد والی جماعتوں کے (روزانہ ڈھائی گھنٹے فارغ کرنے والے) احباب جمع تھے، ان میں حضرت مولاناؒ نے بیان شروع فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا، ہمیں اپنی قربانی کی مقدار کو بڑھانا چاہیے، روزانہ اڑھائی گھنٹے سے بڑھا کر آٹھ گھنٹے فارغ کرنے چاہئیں۔ بندہ بیان کے درمیان بول پڑا، حضرت! یہ آپ رہبانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اگر ایک شخص روزانہ آٹھ گھنٹے فارغ کر لے، اس کے بعد عصر سے اشراق تک، جمعرات کا اجتماع، مہینے کے تین دن، سال کا چلہ، جماعتوں کی نصرت، یہ سب ملا کر نصف سے زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ رہبانیت ہے۔
ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھرے مجمع میں پیش آتا تو ہمارا کیا ردعمل ہوتا؟ بندہ کم از کم اپنی بابت کہہ سکتا ہے کہ میرا نفس تو اسے برداشت نہ کرتا، نہ جانے کیا کہہ دیتا۔ مگر حضرت مولانا نے مجھ جیسے معمولی طالب علم کی بات توجہ سے سنی اور قبول فرمائی۔ بعد میں مجھے اپنی اس حماقت پر سخت ندامت و افسوس ہوا کہ مجھے یہ اشکال تنہائی میں عرض کرنا چاہیے تھا۔ مگر واہ مولانا سعید احمد خانؒ، کیا بے نفسی کی انتہا ہے کہ پورے سکون و بشاشت سے اشکال سن رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ کیا مولانا کے بعد اس کی مثال مل سکے گی؟
؏ اس کوہ کن کی بات گئی کوہ کن کے ساتھ
آپ کی مجلس کے علمی منافع
آپ کی مجلس نہایت باوقار، نصیحت آموز اور علمی منافع کی حامل ہوتی۔ آپ اکثر سکوت و تفکر کی حالت میں ہوتے۔ مجلس لایعنی باتوں، سیاست، حالاتِ حاضرہ پر تبصروں، کسی فرد یا جماعت پر حرف گیری، ابتذال اور استہزا سے بالکل منزہ ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ ایک روحانی مجلس ہے جس پر فرشتوں نے نورانی چادر تانی ہوئی ہے۔ رفقا کی علمی تربیت و ترقی کے لیے مولانا کا ایک خاص طرز یہ تھا کہ کبھی کبھی مجلس میں موجود علما و طلبا سے سوالات فرماتے۔ اس طرح ان میں مطالعہ و تحقیق کا ذوق ابھارتے۔ اکابرین خصوصاً حضرت مولانا الیاسؒ کے بے شمار واقعات سناتے لیکن استشہاد قرآن و سنت اور حضرات صحابہؓ کے واقعات سے کرتے۔ آپ کی مجلس میں لوگ سوالات کرتے اور آپ نہایت بشاشت سے ہر قسم کے سوالات کے جواب مرحمت فرماتے۔
تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا ایسی شخصیت تھے کہ جن سے تبلیغ کے متعلق بھی آزادی سے سوالات کیے جا سکتے تھے۔ آپ نہایت بشاشت سے جواب مرحمت فرماتے۔ بندہ نے عرض کیا بعض تبلیغ والے بیان کرتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، احادیث سے اس کا ثبوت ہے؟ فرمایا، میری نظر سے نہیں گزرا البتہ جمعہ کے بارے میں ایک روایت نظر سے گزری ہے کہ اللہ کے حضور میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔
پھر بندہ نے عرض کیا کہ جماعت کے ایک شخص نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں حضورؐ کے ارشاد فلیبلغ الشاھد الغائب کے بعد صحابہ کرامؓ وہیں سے دنیا بھر میں پھیل گئے اور لاکھوں صحابہ کرامؓ میں سے صرف دس ہزار کی قبریں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں ہیں۔ فرمایا، وہاں سے تو ایک بھی نہیں گیا تھا، رہا قبروں کا معاملہ تو اول تو سارے صحابہؓ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں تھے اور مقبروں کی تعداد کس نے گنی ہے؟ البتہ یہ صحیح ہے کہ بہت سے صحابہ کرامؓ جہاد اور تجارت وغیرہ کے سفروں میں گئے اور دنیا بھر میں مدفون ہیں۔
شبِ عید ہے، مولانا رفقا کو ہدایات دے رہے ہیں کہ یہاں (مدینہ منورہ) کی عید کی نماز بالکل اول وقت میں ہوتی ہے، تمہیں تو شبہ ہو گا کہ ابھی تو اشراق کا وقت بھی ہوا کہ نہیں، اور نمازِ عید ہو جائے گی۔ اس لیے تہجد کی نماز مسجد نبویؐ میں پڑھ کر اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا اور جتنی بار امام تکبیر کہے تم بھی کہتے رہنا۔ (مدینہ منورہ میں تکبیرات زوائد کی تعداد نو یا تیرہ ہوتی ہے)۔ ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا، حضرت! عید کا مصافحہ تو ثابت نہیں ہے۔ فرمایا، میاں یہ مسئلے تم اپنے ملکوں میں رکھو، یہاں تو مصافحہ و معانقہ سے بھی آگے بہت کچھ ہو گا (یعنی پیشانی اور شانوں کا بوسہ)۔ وہ عجیب دن تھے، محفلِ پیر مے خانے کے دم سے پر رونق رہتی۔ ساتھ ہی ایسا علمی و عملی دعوتی ماحول بنتا کہ چند دنوں میں انسان کو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی اور بقدرِ استعداد ہر شخص پر دین کی محنت و دعوت کا رنگ چڑھ جاتا۔
اعتدال و جامعیت
آپ دین کے دوسرے شعبوں میں مشغول علما کی پوری قدر و منزلت فرماتے۔ ہر طبقے اور ہر شعبے سے متعلق علما و مشائخ کثرت سے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہندوپاک کے کتنے ہی علما و مشائخ ہیں جن سے بندہ پہلی بار حضرت مولانا کی مجلس میں متعارف ہوا۔ اسی طرح بندہ بہت سے ایسے علما و مشائخ کو جانتے ہے جو بوجوہ تبلیغی جماعت اور کام سے دور اور وحشت زدہ ہیں، مگر وہ حضرت مولانا سعید احمد خانؒ کو اللہ کا خصوصی مقرب بندہ اور ولیٔ کامل سمجھتے ہیں، حضرت مولانا کے اخلاقِ عالیہ و صفاتِ جلیلہ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی! مولانا سعید احمد خانؒ کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں، وہ اللہ کے مخصوص بندے اور کامل ولی ہیں، ان کی ہستی خدا کا خصوصی انعام ہے۔ حضرت مولانا مرحوم کی وسعتِ قلبی کا یہ عالم تھا کہ لندن تشریف آوری کے موقع پر متعدد بار بندہ سے فرمایا، اہلِ حدیث، جماعتِ اسلامی اور بریلوی اکابر کے پاس ملاقات کے لیے لے چلو۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت کی نقل بلکہ مقابلے پر مولوی الیاس قادری نے کچھ عرصے سے ایک سنی تبلیغی جماعت شروع کر رکھی ہے، حضرت مولانا نے کئی بار ان سے ملاقات کا واقعہ سنایا۔ حضرت مولانا، مولوی الیاس قادری صاحب سے ملنے خود تشریف لے گئے۔
حضرت مولانا کے مزاج میں عجیب جامعیت تھی۔ آپ کسی بھی دینی شعبے کی ناقدری یا اس کی اہمیت کم کرنے کو برداشت نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے، اگر اخلاص ہو تو دین کا کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہے۔ ساتھیوں کے بیان میں اگر کوئی ایسی بات محسوس فرماتے تو فورًا تنبیہ فرماتے۔ ایک بار ایک مولوی صاحب نے دعوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر علم یا ذکر کے شعبے کا اس طرح ذکر کر دیا جس سے ان کے دعوت سے کم تر ہونے کا پہلو نکل سکتا تھا۔ فورًا بلا کر فرمایا کہ بعض مقررین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں حضرات انبیاء علیہم السلام سے تقابل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر حضورؐ کی سیرت و فضیلت کے بیان میں کسی بھی نبی میں نقص کا شائبہ بھی پیدا ہوا تو اس کے یہ معنٰی ہوا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبیؐ ناقص نبیوں کے سربراہ و امام تھے۔ چاہیے کہ ہر نبی کا کمال و فضیلت ثابت کر کے پھر یہ ثابت کریں کہ ہمارے نبی ایسے کاملین اور فضیلت مآب گروہ کے سردار اور امام ہیں۔ اسی طرح بعض مقررین دعوت کی اہمیت اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے علم یا ذکر کی تنقیص مترشح ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ علم و ذکر کی پوری اہمیت و فضیلت بیان کریں، پھر کہیں کہ ایسے اوصاف والے لوگ دعوت میں لگیں تو نور علیٰ نور ہو جائے گا، دعوت کے کام کے اصل حقدار تو یہی لوگ ہیں۔
حضرت مولانا جیسی جامع الصفات ہستی کا اٹھ جانا امت کے لیے سخت ابتلا و آزمائش ہے، خصوصاً تبلیغی جماعت کے لیے۔ اب آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بعض ذمہ داروں میں دین کے دوسرے شعبوں کی بے وقعتی پیدا ہو رہی ہے اور کسی قدر کام میں غلو بڑھ رہا ہے اور علما کی ناقدری روزافزوں ہے۔ ایسے وقت میں مولانا جیسی دین کے ہر شعبے کی قدردان اور معتدل مزاج ہستی کا دنیا سے اٹھ جانا تبلیغی جماعت کا سخت نقصان ہے۔ یوں تو اس قحط الرجال کے دور میں جو بھی شخصیت اٹھتی ہے اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتی ہے، حضرت مولانا کی وفات سے تبلیغی جماعت کا ایک زریں دور ختم ہو گیا ہے۔
پروفیسر خالد ہمایوں کا مکتوب
پروفیسر خالد ہمایوں
لاہور
۱۵ اگست ۲۰۰۱ء
مدیر محترم ’’الشریعہ‘‘
السلام علیکم
’’الشریعہ‘‘ باقاعدگی سے مل رہا ہے، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم دین میں مزید اضافہ فرمائے۔ ’’الشریعہ‘‘ مواد اور پیش کش کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا ہے۔ سنجیدہ فکری جریدے کے یہی نین نقش ہونے چاہئیں۔ یہ جو آپ نے دوسرے حلقہ ہائے فکر کے بارے میں کافی صلح پسندانہ رویہ رکھا ہوا ہے تو یہ امر قابلِ تحسین ہے، اس کی آج بہت ضرورت ہے۔ اگست کے شمارے میں امریکی نائب وزیر خارجہ کے دورۂ پاکستان پر آپ نے فکر انگیز اداریہ تحریر کیا ہے۔ عمار خان ناصر کا مضمون ’’غیر منصوص مسائل کا حل‘‘ اس حوالے سے پسندِ خاطر ہوا کہ اس میں جدید ترین مسائل کا نہایت سلاست کے ساتھ دینی نقطۂ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے۔
مدیر محترم! یوں تو ہمارا معاشرہ مسائلستان بنا ہوا ہے اور سب مسائل کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ دو مسئلوں پر علما اور دانشور حضرات سے مسلسل کچھ لکھواتے رہیں تو بہت مفید ہو گا۔
ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جادو ٹونے کے اڈے گلی گلی میں کھل گئے ہیں، ان کی وجہ سے بے شمار گھر تباہ اور برباد ہو گئے ہیں۔ تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ٹی وی پر ایک نابینا بچے کی گفتگو سنی، وہ قرآن کا حافظ تھا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم پیدائشی طور پر نابینا ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری نظر بالکل ٹھیک تھی، محلے کی کسی عورت نے اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے جادو ٹونہ کروایا اس کا اثر مجھ پر یوں پڑا کہ میری بینائی جاتی رہی لیکن اس کا بچہ صحت یاب ہو گیا۔ کئی سال سے میں خود بھی ایسے اثرات کا سامنا کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا، اس پر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو یہ کتنا اذیت ناک روگ لگا ہوا ہے لیکن کسی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی۔ ہم کس قدر بے حس اور سنگ دل ہو گئے ہیں۔ ہم تیزی سے زوال کی نشانیاں قبول کر رہے ہیں لیکن احساس تک نہیں۔
دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کے امیر طبقے کا ہے۔ میرا خیال ہے اسلام اجازت تو نہیں دیتا کہ طبقاتی منافرت پیدا کی جائے لیکن عملاً یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ چند نہایت با اختیار اور نہایت امیر طبقے ساری قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امیر طبقے میں کچھ خدا ترس لوگ بھی ہیں لیکن کثیر تعداد ایسے لوگوں ہی کی ہے جن کے دلوں اور دماغوں پر زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے اور اپنے رہن سہن کو زیادہ سے زیادہ پرتعیش بنانے کا بھوت بری طرح سوار ہے۔ اس معاملے میں وہابی، سنی، مقلد، غیر مقلد، شیعہ، سیکولر یا اسلام پسند کی کوئی تخصیص نہیں، الا ما شاء اللہ۔ تمام تاجر اور صنعت کار لوگ تقریباً ایک جیسی ذہنیت اور طرزعمل رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے حقوق اور مفادات کے لیے اکٹھے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور منصوبے بناتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو رہے ہیں، خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈکیتیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، کئی کئی کنالوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیوں سے ڈاکو کئی کئی سو تولے زیور، بانڈز اور قیمتی پارچہ جات لے کر راہِ فرار پکڑتے ہیں۔
مدیر محترم! مجھے تو فرقہ واریت کی بھڑکتی ہوئی آگ کے پیچھے سراسر اقتصادی محرکات ہی نظر آتے ہیں۔ بالائی طبقوں کو پھیلتے ہوئے اسلحہ پر بہت تشویش ہے، انہیں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ اسلحہ بردار لوگ سیدھے سیدھے ان کی کوٹھیوں کے اندر نہ آجائیں اور حضرت ابوذرغفاریؓ کا وہ سوال ان کی زبانوں پر نہ ہو کہ تم نے یہ اتنی دولت کہاں سے لی ہے؟
مدیر محترم! آپ جانتے ہی ہوں گے کہ قرنِ اول کے مسلم معاشرے میں جب اونچے اونچے مکانات بننے لگے تھے اور لوگ ذرا با سہولت زندگی بسر کرنے لگے تھے تو حضرت ابوذرغفاریؓ نے کتنا احتجاج کیا تھا۔ میں نے ابھی جادو ٹونے کا ذکر کیا ہے، دیکھا جائے تو اس کاروبار کو بھی مستحکم کروانے والے یہی دولت مند لوگ ہیں، انہی کی پالیسیوں کے نتیجے میں دولت چند ہزار گھرانوں میں مرکوز ہو گئی ہے اور باقی معاشرہ تنگ نظری، کمینگی، حسد اور کڑھن کی آگ میں جل رہا ہے۔
میری تجویز ہے کہ ’’الشریعہ‘‘ میں ایسی تحریریں زیادہ سے زیادہ شائع کریں جن میں ان طبقوں کو سمجھایا جائے کہ وہ دولت کے حصول کے ذرائع بھی ٹھیک کریں اور دولت کی نمائش سے بھی گریز کریں۔ حضرت مولانا سرفراز صاحب نے حضرت عیسٰی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کا واقعہ لکھا ہے، میری ان سے التماس ہے کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس پر لکھیں کہ اس وقت جناب مسیح کو یہ کیوں کہنا پڑا تھا کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے اور گھروں میں کیا بچا کے آئے ہو۔ بعض علما اس واقعہ سے حضرت عیسٰی علیہ السلام کی غیب دانی ثابت کرتے ہیں حالانکہ حضرت عیسٰی کا مطلب یہ تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو حرام تمہارے پیٹوں میں ہے اور جو کچھ تم گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ یہی بات اس طبقے کے لیے تکلیف دہ تھی اور اسی وجہ سے وہ حضرت عیسٰی کے درپے آزار ہو گئے تھے۔
دراز نفسی کی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کے لیے اور زیادہ توفیق اور ہمت سے نوازے۔
والسلام، خیر اندیش
خالد ہمایوں
اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ پنجابی
یونیورسٹی اورینٹل کالج، لاہور
ملک بھر کے علماء کرام و ائمہ مساجد سے اپیل
نمازِ فجر میں قنوتِ نازلہ کا اہتمام کیجئے
مولانا فداء الرحمٰن درخواستی
محترمی علماء کرام و ائمہ مساجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور امارتِ اسلامی افغانستان سمیت پورے عالمِ اسلام بالخصوص دینی حلقوں کو عالمی کفر و استعمار بالخصوص امریکہ اور اس کے حواریوں کے معاندانہ طرزعمل کی وجہ سے درپیش سنگین صورتحال کے پیش نظر جناب رسآلتماب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازِ فجر میں قنوتِ نازلہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں اور عام دعاؤں میں بھی اپنے مظلوم بھائیوں اور مجاہدین کو مسلسل شریک رکھیں۔
قنوتِ نازلہ
نمازِ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قومہ کی حالت میں امام صاحب یہ دعا بلند آواز سے پڑھیں اور مقتدی ہر جملہ پر آہستہ آمین کہیں۔
اَللّٰھُمَّ اھْدِنَا فِیْ مَنْ ھَدَیْتَ وَ عَافِنَا فِیْ مَنْ عَافَیْتَ وَ تَوَلَّنَا فِیْ مَنْ تَوَلَّیْتَ وَ بَارِکْ لَنَا فِیْ مَا اَعْطَیْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَیْتَ فَاِنَّکَ تَقْضِیْ وَ لَا یُقْضٰی عَلَیْکَ اِنَّہٗ لَا یَعِزُّ مَنْ عَادَیْتَ وَ لَا یَذِلُّ مَنْ وَّالَیْتَ تَبَارَکْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَیْتَ نَسْتَغْفِرُکَ وَ نَتُوْبُ اِلَیْکَ اَللّٰھُمَّ انْصُرِ الْاِسْلَامَ وَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰھُمَّ اَیِّدِ الْاِسْلَامَ وَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰھُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِیْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم وَاجْعَلْنَا مِنْھُمْ وَاخْذُلْ مَنَ خَذَلَ دِیْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنْھُمْ اَللّٰھُمَّ اَنْجِ الْمُسْلِمِیْنَ الْمُسْتَضْعَفِیْنَ مِنْ اَھْلِ اَفْغَانِسْتَانَ وَ کَشْمِیْرَ وَ فَلَسْطِیْنَ وَ الشِّیْشَانِ وَ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ اَللّٰھُمَّ اخْذُلِ الْکَفَرَۃَ وَالْھُنُوْدَ وَ الْیَھُوْدَ وَالنَّصَارٰی وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْاَمْرِیْکِیِّیْنَ وَ مَنْ وَّالَاھُمْ مِنَ الْکَافِرِیْنَ وَالْمُنَافِقِیْنَ اَللّٰھُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَکَ عَلَیْھِمْ اَللّٰھُمَّ شَتِّتْ شَمْلَھُمْ اَللّٰھُمَّ فَرِّقْ جَمْعَھُمْ اَللّٰھُمَّ دَمَّرْ دِیَارَھُمْ اَللّٰھُمَّ زَلْزِلْ اَقْدَامَھُمْ اَللّٰھُمَّ فُلَّ حَدَّھُمْ اَللّٰھُمَّ خُذْھُمْ اَخْذَ عَزِیَزٍ مُّقْتَدِرٍ وَاَنْزِلْ بِھِمْ بَاْسَکَ الَّذِیْ لَا تَرُدُّہٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالیٰ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَ خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔
ترجمہ: ’’اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت دی، جن کو تو نے عافیت بخشی اور جن کو تو نے اپنا دوست بنایا۔ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور اپنی قضا کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ کیونکہ تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ یا اللہ! جس کا تو دشمن ہو جائے وہ عزت نہیں پا سکتا اور جس کا تو دوست بن جائے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تیری ذات نہایت بلند اور بابرکات ہے۔ ہم تیری مغفرت چاہتے اور تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ! اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ! اسلام اور مسلمانوں کی تائید فرما۔ اے اللہ! جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرتے ہیں ان کی نصرت فرما اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت نہیں کرتے ان کی نصرت نہ فرما اور نہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اے اللہ! افغانستان، کشمیر، فلسطین، چیچنیا اور ہر جگہ کے کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ! کفار، ہنود، یہود، نصارٰی، مشرکین اور امریکیوں اور ان کا ساتھ دینے والے تمام کفار اور منافقین کو رسوا فرما دے۔ اے اللہ! ان کو سختی سے کچل دے۔ یا اللہ! ان کی جمعیت کو منتشر اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دے۔ یا اللہ! ان کے گھروں کو برباد کر دے۔ یا اللہ! ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ یا اللہ! ان کی دھار کو کند کر دے۔ یا اللہ! قدرت اور غلبے کے ساتھ ان کی گرفت فرما اور ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرما جس کو تو مجرم قوم سے ہٹاتا نہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں ہوں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل اور اصحاب پر۔‘‘
والسلام، منجانب
(مولانا) فداء الرحمٰن درخواستی
امیر پاکستان شریعت کونسل
جامعہ انوار القرآن، آدم ٹاؤن، 1۔C۔11 نارتھ کراچی
ذکرِ الٰہی کی برکات
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
قرآن مجید میں ہے:
ولذکر اللّٰہ اکبر۔
’’اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔‘‘
نماز اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے جس کے قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال کو اگر درجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا درجہ ذکر کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے:
ما من شئی انجٰی من عذاب اللّٰہ من ذکر اللّٰہ۔
’’اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔‘‘
سورۃ الاحزاب میں اللہ کا فرمان ہے:
یا ایھا الذین امنوا اذکروا اللّٰہ ذکرًا کثیرًا (آیت ۴۱)
’’اے ایمان والو! اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔‘‘
سورۃ الانفال میں فرمایا:
واذکروا اللّٰہ کثیرًا لعلکم تفلحون (آیت ۴۵)
’’لوگو! اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔‘‘
یہ لسانی ذکر ہے جس میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات، استغفار اور حمد و ثنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور یہ ذکر کی عام صورت ہے۔ اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے اس کا شکر ادا کرنا قلبی ذکر ہے۔ حصن حصین کی ایک روایت میں ہے کہ
کل مطیع للّٰہ فھو ذاکر۔
’’ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔‘‘
یعنی ہر نیکی کا کام انجام دینے والا آدمی ذاکر ہے۔ تاہم آسان ذکر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:
ان تفارق الدنیا ولسانک ربط من ذکر اللّٰہ۔
’’تو ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔‘‘
ایک موقع پر آپ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے کہ سامنے جمدان نامی پہاڑ آیا، آپ نے فرمایا:
سیروا ھذا جمدان سبق المفرّدون۔
’’یہ جمدان پہاڑ ہے اور مفرد لوگ سبقت لے گئے۔‘‘
پہاڑ کا ذکر آپ نے اس لیے کیا کہ پہاڑ اور شجر و حجر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر صحابہؓ نے عرض کی حضرت! مفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:
الذاکرون اللّٰہ کثیرًا والذاکرات۔
’’یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔‘‘
نومبر ۲۰۰۱ء
دنیا میں معاشی توازن قائم کرنے کا واحد راستہ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
۱۶ اکتوبر کو دنیا بھر میں ’’عالمی یومِ خوراک‘‘ منایا گیا اور اس سال اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ’’غربت کی کمی کے لیے بھوک سے لڑیں‘‘ کے عنوان سے اس موضوع پر مختلف تقریبات، مقالات، رپورٹوں اور خبروں کا اہتمام کیا گیا۔ عالمی سطح پر خوراک اور غربت کی صورت حال کے بارے میں ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں دنیا کی غریب اقوام اور غربت و ناداری کی زندگی گزارنے والے کروڑوں انسانوں کی حالتِ زار کے بارے میں اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صومالیہ، افغانستان اور برونڈی اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ نیم فاقہ کش ملک شمار ہوتے ہیں اور دنیا میں کم و بیش نوے کروڑ انسان ایسے ہیں جنہیں صرف اس قدر خوراک میسر آتی ہے کہ وہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھ سکیں۔ ان میں سے ۸۰ کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت کی اس رپورٹ میں جسے ’’سٹیٹ آف فوڈ ان سکیورٹی ان دی ورلڈ ۲۰۰۰ء‘‘ کا عنوان دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ سخت قسم کی غذائی مشکلات کے حامل ممالک میں افغانستان، بنگلہ دیش، ہیٹی، عوامی جمہوریہ کوریا، صومالیہ اور برونڈی سمیت صحارا اور افریقہ کے ۱۶ دوسرے ممالک شامل ہیں جبکہ کم نوعیت کی غذائی محرومی کے شکار ممالک میں پاکستان اور بھارت بھی شمار ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں خشک سالی اور جنگوں سے پیدا شدہ صورتِ حال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور غربت، خوراک کی کمی اور ناداری کو دور کرنے کے لیے عالمی سطح کی کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔
رپورٹ کی تفصیلات و جزئیات کا احاطہ اس موقع پر ضروری نہیں ہے البتہ اس حوالے سے غربت، ناداری اور بھوک کے عالمی تناظر میں اصولی طور پر اس بات کا جائزہ لینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس غربت و ناداری اور بھوک و افلاس کے اسباب کیا ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کے لیے عالمی سطح پر آج کے دور میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے اور آج کی بین الاقوامی قوتوں اور اداروں کی پالیسیوں کی بنیاد اسی نقطہ نظر پر ہے کہ آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے اور دنیا کے موجود اور میسر وسائل آبادی میں اس تیز رفتار اضافے کا ساتھ نہیں دے رہے جس سے عدمِ توازن پیدا ہو گیا ہے اور بھوک اور غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آبادی میں اضافے کو روکا جائے اور انسانی آبادی میں شرحِ پیدائش کو خوراک اور دیگر وسائل میں اضافہ کی رفتار کے ساتھ منسلک کر کے کنٹرول میں لایا جائے۔
آبادی میں اضافے پر کنٹرول کی اس عالمی پالیسی سے جو معاشرتی خرابیاں جنم لے رہی ہیں اور پریشان کن مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مگر ان سے قطع نظر اسلامی نقطہ نظر سے اور معروضی حقائق کے حوالے سے سرے سے یہ بنیاد ہی غلط ہے اور محض ایک مفروضہ ہے جسے بہت سے جائز اور ناجائز مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور اسے چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سب انسان اسی نے پیدا کیے ہیں اور زمین میں ان کے لیے خوراک بھی اسی نے مہیا کی ہے۔ اسے انسانوں کی ضروریات اور زمین میں خوراک کے خزانوں کی مقدار کا علم ہے ۔ وہ انسانوں کی ضروریات سے غافل نہیں ہے اور نہ آبادی اور خوراک کے ذخائر میں توازن قائم رکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اس نے ہر جاندار کی خوراک کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس وعدہ کے مطابق وہ صرف انسانی آبادی نہیں بلکہ ہر جاندار مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک اور دیگر ضروریات مہیا کر رہا ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اس میں روح ڈالی اور دنیا میں اس کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق خوراک مہیا نہیں کی کیونکہ یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے دو تین کا تذکرہ مناسب خیال کرتا ہوں۔
سورہ ہود کی آیت ۶ میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے:
’’زمین میں رینگنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ ہر جاندار کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کو جانتا ہے اور یہ سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے۔‘‘
سورۂ ابراہیم کی آیت ۳۴ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:
’’اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا‘‘
یہاں یہ اشکال سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانوں نے ان نعمتوں کا کوئی سوال تو نہیں کیا اور نہ اپنی ضروریات کی کوئی فہرست پیش کی تو مفسرینِ کرام نے کہا کہ یہاں سوال سے مراد زبانِ حال کا سوال ہے اور مشہور مفسر قاضی بیضاویؒ نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ’’اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو سوال کے قابل تھی‘‘ یعنی ہر وہ چیز جس کے سوال کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، وہ بغیر سوال کے مہیا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسانی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں اور کسی ضرورت کو ادھورا نہیں چھوڑا البتہ ان تک رسائی اور ان کے حصول کے لیے اسباب کا واسطہ بنا دیا اور حکم دیا کہ اسباب کے درجے میں محنت کر کے اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کر لو۔
سورہ حٰم السجدۃ آیت ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں بنایا اور پھر دو دن میں اس میں خوراک کے ذخیرے ودیعت کیے۔ اس سے آگے ایک جملہ ہے: سواء للسائلین۔حضرت حسن بصریؒ ، امام ابن جریر طبریؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے خوراک کے ذخیرے ’’ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہیں‘‘ یعنی زمین کی پشت پر جتنی آبادی ہوگی، زمین کے پیٹ میں اس کی ضرورت کے مطابق خوراک موجود رہے گی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جانداروں کی خوراک کی ذمہ داری اٹھائی ہے بلکہ خوراک کے ضرورت مندوں کی تعداد اور خوراک کے ذخائر کی مقدار کے درمیان توازن قائم رکھنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا وعدہ کریں اور اسے اپنی ذمہ داری ٹھہرا لیں اور پھر نعوذ باللہ اس سے غافل ہو جائیں۔
اس لیے مسئلہ انسانی آبادی میں اضافے کی رفتار اور زمین میں خوراک کے ذخائر کی مقدار میں توازن کا نہیں ہے کیونکہ اس توازن کو قائم رکھنے اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق خوراک اور دیگر ضروریات مہیا کرنے کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ مسئلہ اس سے آگے ہے جو اسباب سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں دو پہلو قابلِ توجہ ہیں: ایک یہ کہ زمین میں موجود خوراک کے ذخائر تک رسائی کس طرح ہو اور دوسرا یہ کہ ان کی تقسیم کا کیا نظام ہو؟ کیونکہ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے کی ہیں اور انہیں انسان کی عقل اور دیانت کی آزمائش ٹھہرایا ہے۔ گڑبڑ اسی مقام پر ہے اور ہمیں اس گڑبڑ کا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے تاکہ خرابی کے اصل مقام کا تعین ہو اور اسے دور کرنے کے لیے صحیح سمت میں کوشش کی جا سکے۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی فلاحی مملکت میں ہر کنبے کو اس کی ضرورت کے مطابق وظیفہ دیا جاتا ہو اور پندرہ بیس افراد کے ایک کنبے کے سربراہ کو اتھارٹی دی جائے کہ وہ اپنے کنبے کے افراد کی ضروریات کے لیے اتنی رقم سرکاری خزانے سے لے سکتا ہے مگر وہ اپنے کنبے کی ضرورت کی رقم سرکاری خزانے سے وصول کرنے میں بے پروائی کرتا ہے یا وہاں سے وصول کر لیتا ہے اور متعلقہ لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے ذاتی عیش و عشرت پر ضائع کر دیتا ہے تو اس کنبے کے افراد کو خوراک و لباس اور دیگر ضروریات نہ ملنے کی ذمہ داری اس فلاحی ریاست پر نہیں ہوگی بلکہ کنبے کا سربراہ اس بات کا مجرم ہوگا کہ اس نے رقم وصول نہ کر کے یا وصولی کی صورت میں بے جا تعیش پر صرف کر کے اپنے کنبے کے افراد کو بھوک، ناداری اور غربت سے دوچار کر دیا ہے۔
اسی طرح آج اگر دنیا میں کروڑوں انسان بھوک اور فاقہ کا شکار ہیں اور بہت سے ممالک اپنے عوام کو بنیادی ضروریات مہیا کرنے سے قاصر ہیں تو اس کا قصور وار وہ نظام اور سسٹم ہے جس نے انسانی برادری کی عالمی سطح پر چودھراہٹ سنبھال رکھی ہے اور جس نے خوراک کے ذخائر اور دنیا کے مالی وسائل پر اجارہ داری قائم کر کے ان کی تقسیم کے تمام اختیارات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ دنیا کے مالی وسائل اور خوراک کے ذخائر پر چند ممالک کی اجارہ داری اور ان کی تقسیم کے ترجیحی نظام کا کرشمہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اپنی پیدا کردہ گندم کا ایک بہت بڑا حصہ زائد از ضرورت قرار دے کر سمندر میں پھینک دیتا ہے اور برطانیہ میں مارکیٹ کی قیمتوں میں توازن رکھنے کے لیے کچھ زمینداروں کو گندم کاشت کرنے سے سرکاری طور پر روکا جاتا ہے اور دوسری طرف غریب ممالک میں لاکھوں انسان بھوک سے مر جاتے ہیں۔ ایک طرف امیروں کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف غریبوں کی غربت اس سے دگنی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ خود ہمارے ملک میں ایک طرف چند افراد اور خاندان ہیں جن کے کتے مکھن اور پنیر کھاتے ہیں اور دوسری طرف کروڑوں غریب عوام ہیں جن کے بچوں کو دو وقت سادہ روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ غربت کا مسئلہ قومی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، دونوں جگہ خرابی کا باعث تقسیم کا نظام ہے اور وہ خود غرض طبقات و اقوام اس کے ذمہ دار ہیں جو اپنی عیاشی اور لگژری کے لیے غریب عوام و طبقات کا استحصال کر رہی ہیں اور کروڑوں بھوکے اور فاقہ کش انسانوں کے منہ سے نوالے چھین کر اپنی تجوریاں بھر رہی ہیں۔ تقسیم کے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ زمین کے وسائل پر تمام انسانوں کا یکساں حق تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تعیش و لگژری اور غربت و فاقہ کی دونوں انتہاؤں کی نفی کرتے ہوئے ضروریات کی باوقار فراہمی کے معتدل اور متوازن اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ایک عدد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے جو خلیفہ کی حیثیت سے وظائف تقسیم کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ازواج مطہرات اور اصحابِ بدر کو زیادہ وظیفہ دینے اور باقیوں کو کم دینے کی درخواست کو یہ کہہ کر مسترد کر دیں کہ ’’یہ معیشت کا شعبہ ہے۔ اس میں برابری کا اصول ترجیح کے اصول سے بہتر ہے۔‘‘
غربت و ناداری پر قابو پانے اور فاقہ و افلاس کو ختم کر کے تمام انسانوں کو ضروریات زندگی سے بہرہ ور کرنے کے لیے دنیا کو اسی اصول پر واپس آنا ہوگا۔ اس کے بغیر دنیا میں معاشی توازن قائم کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
نفاذِ شریعت کی ضرورت و اہمیت
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
جب تک برصغیر پر انگریز حکمران رہا اہلِ ایمان اس کے قانون کی پابندی پر مجبور تھے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی قوانین سب انگریز کے وضع کردہ تھے۔ البتہ اس نے مسلمانوں کو بعض رعایات دے رکھی تھیں جن کو پرسنل لاء کہا جاتا تھا اور مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق ان کو اختیار کر سکتے تھے۔ مگر آزادی کے بعد تو انگریزی قانون کے نفاذ کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے قیام کے فورًا بعد تمام قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کر لیا جاتا مگر افسوس کہ آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں کارپردازانِ حکومت خاص طور پر اور عام مسلمان عام طور پر گنہگار ہیں کہ وہ شریعتِ اسلامیہ کو نافذ نہیں کر پائے۔ آج تک وہی ملعون قوانین چل رہے ہیں۔ مثلاً حادثاتی موت کی صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سودی کاروبار بالکل اسی طرح چل رہا ہے جیسے انگریزوں کے زمانے میں تھا۔ عدالتی نظام میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی بلکہ وہی غلامانہ تعزیراتی قانون رائج ہے۔
دیکھیں، ترکی میں شریعت کا قانون ختم ہوا تو ملکی قانون بھی بدل دیے گئے اور پھر کوئی قانون جرمنی کا، کوئی برطانیہ کا، اور کوئی فرانس کا لے لیا گیا۔ اور اس طرح آدھا تیتر آدھا بٹیر والی مثال صادق آئی۔ خود ہمارے ملک میں شریعت کا نفاذ اس بہانے سے نہیں کیا جا رہا کہ اس پر تمام مذاہب متفق نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح چور دروازے سے حکومت پر قابض رہیں۔ اگر خدا کا قانون جاری ہوتا ہے تو ان کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے لہٰذا خیریت اسی میں ہے کہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے۔ تعزیراتی قوانین میں شرع کے مطابق کچھ ردوبدل کیا گیا ہے مگر اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔
سعودی عرب میں حدود کا نفاذ ہے تو وہاں جرائم بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ بدو تھے جو کبھی مسافر کے پاؤں سے جوتا بھی اتروا لیا کرتے تھے، مگر آج اسلامی تعزیرات کے نفاذ کا یہ اثر ہے کہ سڑک پر سونے کی ڈلی بھی پڑی ہو تو کوئی ہاتھ لگانے کی جرأت نہیں کر سکتا بلکہ پولیس کو دور سے ہی بتا دیتا ہے کہ وہاں کسی کا مال پڑا ہے۔ آج لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں مگر کسی کی کیا مجال ہے کہ چوری تصور بھی کر سکے۔ اب تک زیادہ سے زیادہ پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہاتھ کٹے ہوں گے مگر چوری بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور ہمارے ہاں شرعی قوانین سے انحراف کی وجہ سے لوگ مسجد سے جوتے تک چوری کر لیتے ہیں۔
باقی رہا یہ اعتراض کہ کون سا فقہی قانون نافذ کیا جائے تو یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسلّمہ اصول ہے کہ جس ملک میں جس فقہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں اسی فقہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ اسپین میں مالکی فقہ کی اکثریت تھی تو وہاں مالکی فقہ رائج رہی۔ برصغیر، افغانستان، ترکی، خراسان وغیرہ میں حنفی لوگوں کی اکثریت ہے تو یہاں حنفی فقہ کے مطابق قانون جاری ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ بعض لوگ حنفی قانون کے نام سے بدکتے ہیں حالانکہ یہ بھی قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ فتاوٰی اور دیگر کتب کی تمام باتیں قابلِ عمل نہیں ہوتیں بلکہ یہ محض معلومات ہوتی ہیں جن پر قانون کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ’’عالمگیری‘‘ سے لوگوں کو خواہ مخواہ چڑ ہے۔ یہ تو پانچ سو علماء کا تدوین کردہ قانون ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
اگر لوگوں کی اکثریت کا قانون جاری کر دیا جائے تو دوسرے لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ حنفی فقہ ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک دنیا میں رائج رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنے آپ کو شافعی ظاہر کیا ہے تو اس کا فیصلہ شافعی مسلک کے مطابق کر دیا گیا اور اس میں کسی مسلک والے کو دقت پیش نہیں آئی۔ مختلف فقہی مسالک میں مکمل اتفاق تو شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ انگریزی قانون میں بھی کبھی جج کسی فیصلہ پر متفق نہیں ہوئے۔ بھٹو کی پھانسی کے مسئلے پر سارے جج متفق نہیں ہوئے تھے بلکہ ان میں بھی اختلافِ رائے تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیاوی قوانین میں تو اس قسم کے اختلافات برداشت کر لیے جاتے ہیں مگر فقہی جزئیات میں ایسے اختلافات کو برداشت نہیں کیا جاتا اور مکمل اتفاقِ رائے تک نفاذِ شریعت کے عمل کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ بہرحال شریعت کا قانون من جانب اللہ ہے جس میں تمام کلیات اور جزئیات آ گئے ہیں اور پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں اس کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
عصرِ حاضر میں اسلام کی تعبیر و تشریح
مولانا محمد عیسٰی منصوری
(زیرِنظر تحریر میں مولانا محمد عیسٰی منصوری نے دورِ حاضر میں دعوتِ اسلام کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس موضوع پر ہم دیگر اہلِ علم کی سنجیدہ فکری تحریروں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ مدیر)
مغرب میں مسلمانوں کے مستقبل کا دارومدار اس بات پر ہے کہ وہ اسلام کے پیش کرنے میں کیا حکمتِ عملی اختیار کرتے ہیں۔ ایک طبقہ اسلام کو محض نظامِ اقتدار بنا کر پیش کر رہا ہے جس کے نتیجے میں مقامی آبادی میں اسلام سے وحشت پیدا ہو رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان یہاں اقتدارِ اعلٰی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ صحیح طریقہ یہ تھا کہ اسلام کے نظامِ عقائد کو پیش کیا جاتا یعنی اسلام کے نظریہ و فکر کو، جو آج کے نظریاتی دور اور اہلِ مغرب کی نفسیات کے عین مطابق ہوتا اور مغربی اقوام کو سنجیدگی اور کھلے دل سے اس پر غور کرنے کا موقع ملتا۔ چنانچہ مدیر ’’الرسالہ‘‘ جناب وحید الدین خان ایک جگہ لکھتے ہیں:
’’ہر انسانی گروہ کا ایک نظامِ عقائد ہوتا ہے اور اس کا نظامِ اقتدار۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان نظامِ اقتدار کے اعتبار سے دوسری قوموں سے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن نظامِ عقائد (فکر و نظریہ) کے اعتبار سے آج بھی وہ تمام قوموں سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر مسلمانوں کے قائدین ساری دنیا میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ نظامِ اقتدار کے میدان میں دوسری قوموں سے ٹکرا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے حصے میں شکست و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ اس بے فائدہ ٹکراؤ کو ختم کر دیں اور نظامِ عقائد کے میدان میں دوسری قوموں کو اپنا مخاطب بنائیں تو بہت جلد وہ دیکھیں گے کہ ان کی شکست کی تاریخ فتح کی تاریخ میں تبدیل ہو گئی ہے۔‘‘
۱۹۹۴ء میں امریکہ میں عالمی مذاہب کانفرنس ہوئی جو ہر سو سال بعد منعقد ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مذہب کے پیروکاروں کو اپنے مذہب کا تعارف پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والی ایک علمی شخصیت نے اس کانفرنس کا ایک نہایت قابلِ غور نکتہ تحریر کیا ہے۔ وہ یہ کہ کانفرنس میں دوسرے مذاہب پر گفتگو کے دوران لوگ سنجیدہ رہتے اور بغور سنتے، مگر جونہی اسلام کے تعارف کا موقع آجاتا وہ جارحانہ انداز اختیار کر لیتے۔ لوگوں کے اس رویہ کا سبب بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے نمائندے اپنے مذہب کو فرد کی تعمیر کی حیثیت سے پیش کرتے یعنی ان کا مذہب فرد کے اعمال و عقائد میں کیا تبدیلی چاہتا ہے- اس کے برعکس اسلام کا نمائندہ اپنی بات یہاں سے شروع کرتا کہ اسلام ایک مکمل نظامِ حیات ہے، وہ پورے اجتماعی نظام میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ غرض وہ اسلام کو ایک کامل ریاستی نظام کی حیثیت سے پیش کرتا یعنی فرد کے بجائے ریاست کے حوالہ سے۔ یہ بدیہی بات ہے کہ جب سیاست و سسٹم کی بات آئے گی تو سامع پر فوری اثر یہ مرتب ہو گا کہ وہ سمجھے گا کہ مسلمان ہم پر سیاسی بالادستی و اقتدار کے خواہاں ہیں۔ اس طرح خودبخود اسلام کے متعلق ان کا انداز جارحانہ ہو جائے گا اور وہ ذہنی طور پر تناؤ (Tension) کی حالت میں آجائیں گے۔
موجودہ دور کے مسلمانوں میں اسلام کے حوالے سے اس طرزِ فکر کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں میں عالمِ اسلام کے بڑے حصے پر مغرب کی سیاسی حکمرانی رہی ہے۔ اس کے ردعمل کے طور پر بیسیوں صدی کے دورِ غلامی میں نشوونما پانے والے متعدد اسلامی مفکرین کے ذہنوں پر اسلام کا سیاسی پہلو حاوی ہو گیا۔ اس فکر سے مغلوب ہو کر انہوں نے اسلام کی سیاسی تعبیر پیش کرنی شروع کی، کیونکہ اسلام کو ایک ریاستی نظام کے طور پر پیش کرنے میں ان کی غلامی کی مجروح انا کو ایک طرح کی تسکین حاصل ہوتی تھی۔ حالات کے جبر نے ان کے فہمِ اسلام میں یہ انحراف پیدا کر دیا کہ ان کے نزدیک اسلام کا بنیادی ہدف و مقصد فرد کی تعمیر کی بجائے ریاست و اقتدار کا قیام ہے۔ جبکہ فی الواقع اسلام کی یہ تعبیر انتہائی مغالطہ انگیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اصل نشانہ بھی فرد ہے نہ کہ اجتماع۔ اجتماعی تبدیلی اس کا بالواسطہ جز ہے نہ کہ براہِ راست۔ انسانی شخصیت کی تعمیر ہی اسلام کا اصل مقصد ہے جس طرح یہ دوسرے مذاہب کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام کو سیاسی نظام کے انداز میں پیش کرنے کا فوری نقصان یہ ہوتا ہے کہ مخاطب شروع ہی سے تناؤ اور ٹینشن کی کیفیت میں آجاتا ہے اور وہ کھلے دل سے اسلام کی بات سننے اور اس پر غور کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ اس موضوع پر جناب خورشید احمد ندیم صاحب لکھتے ہیں:
’’دین کے ماخذوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا اصل منتہا ایک اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہے، مگر مسلمان چونکہ اللہ تعالٰی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہیں اس لیے جب یہ کہیں مل کر کوئی معاشرت یا ریاست قائم کریں گے تو ان کے اجتماعی نظام میں ایک ناگزیر تقاضے کے طور پر دین ہی کو غلبہ حاصل ہو گا۔ اس اعتبار سے یہ اجتماعیت کے متعلق ایک تقاضہ ہے نہ کہ دین کا نصب العین۔ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھئے۔ اس امت پر شہادتِ حق کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا تقاضہ ہے کہ اگر انہیں کہیں اقتدار ملے تو وہاں وہ اللہ کے دین کو غالب کریں۔ اب نصب العین اور تقاضے کے اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی موجودہ صورتِ حال پر نظر ڈالیے تو جناب وحید الدین خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس وقت اس کیفیت میں نہیں کہ کوئی پولیٹیکل ایمپائر کھڑی کریں۔ البتہ وہ ایک ’’دعوہ ایمپائر‘‘ ضرور قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت مواصلات کی ترقی اور آزادیٔ ابلاغ کی اس فضا کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک عالمی دعوت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا مغرب کے ساتھ کسی مکالمہ میں شریک ہوتے وقت مسلمانوں کو اس پہلو سے بھی غور کرنا ہو گا کہ وہ داعی ہیں اور مغرب ان کا مدعو۔ اس لیے داعی اور مدعو کے مابین تعلق کی صحیح نوعیت ان کے پیشِ نظر رہنی چاہیے۔‘‘
نیز انسانی فطرت کا یہ پہلو بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آدمی ہمیشہ نظریہ کی تصدیق خارج میں چاہتا ہے۔ جب آپ اسلام کو ایک سیاسی نظام کے طور پر پیش کریں گے تو قدرتی طور پر مخاطب اس کی تصدیق کے لیے مسلم ممالک (سعودی عرب، پاکستان، ایران، عراق) کی طرف دیکھے گا۔ جب وہاں کوئی بہتر سسٹم و نظام نہیں پائے گا تو شروع ہی سے اسلام کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کا شکار ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت مغرب میں ٹھنڈے دل سے اسلام پر غور کرنے اور اس کے سمجھنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ افراد و جماعتیں ہیں جنہیں اسلام کی سیاسی تعبیر پر اصرار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی سیاسی تعبیر کا ذہن بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ کی مسلم دنیا پر سیاسی بالادستی کے ردعمل کے طور پر پیدا ہوا۔ بیسویں صدی دنیا میں مختلف ازموں کے عروج و غلغلہ کا دور ہے، کمیونزم، سوشلزم، سیکولرازم، کیپٹل ازم وغیرہ۔ اس سے متاثر ہو کر بعض اسلامی مفکرین نے اسلام کو ایک ازم کے طور پر پیش کیا۔ اسی طرح اسلام کو بطور تحریک پیش کرنا بھی اسی کا حصہ ہے۔ اگرچہ تحریک عربی لفظ ہے مگر قرآن و حدیث، سیر و مغازی حتٰی کہ بیسویں صدی سے پہلے فقہ و ادب میں تحریک کا لفظ شاذ و نادر ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے عام طور پر دعوت کا لفظ مستعمل تھا۔
اس کے برعکس اگر اسلام کو فطری انداز میں پیش کیا جائے تو اس کی تصدیق کے لیے مخاطب انسانی فطرت کی طرف رجوع کرے گا۔ اور یہاں وہ فورًا اس کی تصدیق پا لے گا کیونکہ اسلام کو وہ فطرتِ انسانی کے عین مطابق پائے گا۔ کیونکہ خالقِ کائنات نے اسلام کو فطرت کے عین مطابق اور حق کی بنیاد پر بنایا اس لیے فطری انداز میں پیش کیے جانے والے اسلام کی تصدیق مخاطب بلاتاخیر خود اپنی فطرت اور قلب کی سطح پر پا جاتا ہے، اسے اس کی تصدیق کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جبکہ غیر فطری (سیاسی) انداز میں پیش کیے جانے والے اسلام کی خارج میں تصدیق نہ پا کر مخاطب ابتدا ہی سے اسلام کی حقانیت کے متعلق شبہات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ موجودہ صدی کے بعض اسلامی مفکرین و داعیوں نے اسلام کو ایک سیاسی نظام کے طور پر پیش کر کے نہ صرف دنیا کی اقوام کو اسلام سے دور کیا ہے بلکہ خود اسلام پر بھی بڑا ظلم کیا ہے۔
اس وقت یہ مسئلہ بہت اہم اور قابلِ غور ہے کہ مغرب میں اسلام کی دعوت کے لیے حکمتِ عملی کیا ہو؟ اسلام کے پیش کرنے کا فطری طریقہ یہی ہے کہ مسلمان یہاں اپنے عمل سے اسلام کو پیش کریں۔ اور معتدل انداز میں اسلام کے ان افادی پہلوؤں کو پیش کریں جو ساری دنیائے انسانیت کی بہبود و بھلائی کے لیے ہیں۔ یا علمی طور پر اسلام کے فطرتِ انسانی، جدید سائنس اور دیگر انسانی علوم کے عین مطابق ہونے کو پیش کیا جائے۔ دنیا کے مذاہب میں یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ جدید سائنس اور دیگر انسانی علوم اپنی ترقی کے ہر ہر مرحلہ میں اس کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ وہ آج تک قرآن کی ایک بات کو بھی خلافِ واقعہ ثابت نہیں کر پائے۔ جبکہ دیگر مذاہب کی ڈھیروں باتیں سائنس اور جدید علمی تحقیقات سے ٹکراتی ہیں۔ چنانچہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں:
’’ان (مسلمانوں) کے پاس وہ سچائی ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ تجارتی اصطلاح میں انہیں مذہب کے میدان میں ایک قسم کی اجارہ داری (Monopoly) حاصل ہے۔ تمام اہلِ مذاہب میں وہ تنہا گروہ ہیں جن کے پاس بے آمیز مذہبی صداقت موجود ہے، جن کا مذہب پورے معنوں میں تاریخی مذہب ہے۔ جبکہ دوسرے تمام مذاہب غیر معتبر روایات کا مجموعہ ہیں۔ اسلام کے سوا کسی بھی دوسرے مذہب کو تاریخ کی بنیاد حاصل نہیں ہے۔‘‘
اس وقت مسلمانوں کو سیاسی نظام کے حوالے سے مغرب میں مخاصمت بڑھانے کے بجائے اسلام کے فکر و عقیدہ کو پیش کرتے ہوئے مغرب میں درپیش معاشرتی و اخلاقی بحران پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کی دعوت کا جذبہ رکھنے والے اپنے خول سے باہر نکلیں اور مغرب کے سنجیدہ دانشوروں اور مذہبی طبقہ سے ڈائیلاگ شروع کریں۔ مذہب، آخرت، تمدنی و معاشرتی مسائل، خاندانی نظامِ استحکام، نئی نسل کی بے راہ روی، انسانیت کی اپنے پیدا کرنے والے سے دوری، اور مذہبی گرفت کے کمزور پڑنے کے اسباب جیسے بے شمار عنوانات پر اسلام اور مغرب کے درمیان مکالمے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام دعوت کا مذہب ہے۔ وہ پوری انسانیت کی بہبود کے لیے مستقل نظریۂ فکر رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے جہاں بھی وہ اپنی بات پہنچا سکے۔ تھامس مین نے درست کہا ہے:
’’گفتگو فی نفسہٖ تہذیب ہے۔ لفظ چاہے کتنا ہی اختلافی ہو واسطہ کا ذریعہ بنتا ہے۔‘‘
اس موضوع پر خورشید ندیم صاحب لکھتے ہیں:
’’مغرب سے مکالمے میں جو بات بطور اصول ملحوظ رہنی چاہیے وہ نظریے و سیاست کا تفاوت ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کیا ہیں؟ مشرقِ وسطٰی میں امریکہ نے کیا طرزِ عمل اختیار کر رکھا ہے؟ مسلم اور غیر مسلم ممالک میں تجارت کن بنیادوں پر ہونی چاہیے؟ یہ سوالات عملی سیاست کا موضوع تو ہو سکتے ہیں لیکن کسی نظری بحث کا نہیں۔ اسلام میں ایک ریاست کا قیام کیا فی نفسہٖ مطلوب ہے؟ اسلام میں انسان کے معاشرتی مسائل کا حل کیا ہے؟ سرمایہ داری اور اسلام کی معاشی تعلیمات میں کہاں کہاں ہم آہنگی اور کہاں کہاں فرق ہے؟ یہ سب سوالات ایک نظری بحث کا موضوع ہونے چاہئیں۔ عملاً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسلام اور مغرب کے درمیان کسی مکالمے کا آغاز ہوتا ہے تو روزمرہ کے سیاسی مسائل کچھ اس طرح غلبہ پا لیتے ہیں کہ نظری مسائل دب کر رہ جاتے ہیں۔ میڈیا کو چونکہ سیاسی مسائل سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس لیے وہ اس سارے عمل کو اپنے طور پر متاثر کرتا ہے۔ اس طرح اسلام کا موقف پوری طرح واضح نہیں ہو پاتا۔ عرب مصنفین کی یونین کے سیکرٹری جنرل علی اکلارسان نے درست کہا ہے کہ ’’ہم اس صداقت کے دور میں زندہ ہیں جسے میڈیا سچ کہتا ہے نہ کہ حقیقی سچ‘‘۔ ہوتا یہ ہے کہ اہلِ دانش کی تمام مساعی لاحاصل رہتی ہیں کیونکہ میڈیا کی ساری دلچسپی سیاسی مفادات سے وابستہ ہے اور سیاسی مفادات کا حق و انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔‘‘
سب جانتے ہیں کہ عرصہ سے مغربی میڈیا پر صہیونیت کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے۔ وہ کمال عیاری سے اسلام کی تصویر مسخ کرنے کا کام خود اسلام کے داعیوں سے لے رہا ہے۔ مغرب میں دعوت و فکر کے بجائے خلافت و جہاد کو مقصد قرار دینا مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہاں پرجوش مسلم رہنماؤں کے بیانات سنیں تو ان میں عموماً دو باتیں پائیں گے:
- مسلم حکمرانوں پر غیظ و غضب، اور
- مغرب کے اسلام دشمن رول کو پیش کرنا۔
اس طرزعمل سے مشتعل ہو کر مسلم نوجوان ردعمل کی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ مغربی میڈیا مسلمانوں کو مشتعل دکھانا چاہتا ہے اس لیے وہ ان مسلم رہنماؤں کو زیادہ سے زیادہ کوریج دیتا ہے۔ اس کے دو مقاصد ہیں:
- دنیا میں مغرب کے کھلے پن اور آزادیٔ رائے کا پروپیگنڈا کرنا۔
- ذرائع ابلاغ میں مسلمانوں کی منفی تصویر پیش کرنا تاکہ مقامی لوگوں میں اسلام اور مسلمانوں سے تنفر بڑھتا رہے۔
مسلمانوں کے بعض پرجوش رہنما اپنے طرزعمل سے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام اور مسلمانوں کی منفی اور انتہاپسندانہ تصویر پیش کرنے میں مغربی میڈیا کی معاونت کر رہے ہیں۔
موجودہ دور میں مغرب میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی منفی تصویر (Negative image) بن گئی ہے۔ اس صورتحال کو بدلنا اور مسلمانوں کی مثبت تصویر (Positive image) پیش کرنا وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ کام مسلمانوں کو خود کرنا ہو گا۔ اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مسلمان مغربی میڈیا کے اشتعال دلانے پر بھی مشتعل نہ ہوں۔
الغرض ہمیں مغرب سے مکالمہ کا ایجنڈا ترتیب دیتے وقت اس امر کا بطور خاص خیال رکھنا ہو گا کہ مکالمہ فکری و نظری مسائل پر ہو نہ کہ سیاسی و تہذیبی مسائل پر۔ بصورتِ دیگر جہاں اسلام کی بے شمار تعبیریں سامنے آئیں گی وہاں مسلمانوں اور اہلِ مغرب کے مختلف رویے اس کو پیچیدہ بنا دیں گے، اور باہمی مکالمے کی ساری تگ و دو بحث برائے بحث سے آگے ہی نہیں بڑھ سکے گی، بلکہ اندیشہ ہے کہ مزید منافرت و دوری کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ سیاست و اقتدار وہ شے ہے جس کی بنیاد مفادات پر ہے، اور مفادات بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مسلمانوں نے اسلام کو نظریۂ فکر کے بجائے نظامِ ریاست کے طور پر پیش کیا تو ایک طرف سیاسی مفادات اور دوسری طرف صہیونی میڈیا مغرب میں اسلام کے کیس کو تلپٹ کر کے رکھ دیں گے۔
دورِ نبوت سے لے کر عصرِ حاضر تک اسلام کے فکر و نظریہ اور قرآن کے آفاقی و انفسی دلائل کا کفر کے پاس ہمیشہ ایک ہی جواب رہا ہے، جسے قرآن نے ان معجز نما الفاظ میں بیان کیا ہے ’’لا تسمعوا لھٰذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون‘‘ کہ قرآن کو سنو ہی نہیں اور اگر کوئی سنائے تو مخالفانہ شور و شغب برپا کرو شاید اس طرح تم غالب ہو سکو۔ جس طرح دورِ نبوت میں اسلام کی روشنی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیغمبر اسلام کے ساحر، کاہن، شاعر و مجنون ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا، آج مغرب کی مہذب اقوام نے اسلام کے لیے نئی گالیاں ایجاد کر لی ہیں اور نئے بہتان اور اتہامات تراش لیے ہیں۔ انتہا پسند، بنیاد پرست، انسانی حقوق کے خلاف ہونے کا شور مچا کر مغرب کے ذرائع ابلاغ نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں ضروری ہے کہ مسلمان مغربی میڈیا کے اکسانے پر مشتعل نہ ہوں اور صبر و تحمل سے اسلام کے فکر و نظریہ کو پیش کریں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد حالات ان کے حق میں ہو جائیں گے کیونکہ مغرب میں مذہبی عصبیت بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے۔
گزشتہ کئی صدیوں سے مغرب کے ذہن و فکر کو تشکیل دینے والے بیشتر فلسفی و مفکر یہودی رہے ہیں۔ جیسے ہیگل، کارل مارکس، ڈارون وغیرہ۔ انہوں نے صدیوں کی تگ و دو کے بعد مغرب میں سیاسی، معاشی اور تعلیمی طور پر ایسا نظام قائم کر دیا ہے جس میں ایک اقلیت (یہودی) بآسانی اکثریت پر اثرانداز ہو سکتی ہے اور ان پر کنٹرول کر سکتی ہے۔ یہودیوں کی خفیہ دستاویز (پروٹوکول) سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا پر ایک خاص نسل کے تسلط قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں دوسری کسی بھی اقلیت کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ مسلمان اگر سیاسی محاذ آرائی سے بچتے ہوئے اسلام کو فکری و عملی طور پر پیش کر سکیں تو اس وقت مغرب میں اسلام کے لیے حالات نہایت سازگار ہیں۔ مسلمان مغرب میں وہ حکمتِ عملی اختیار کریں جو حضرت جعفر طیارؓ نے حبشہ میں مسیحی بادشاہ نجاشی کے ملک میں اختیار کی تھی۔ حضرت جعفر طیارؓ کے حضرت عیسٰی علیہ السلام کے متعلق عقیدہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا ’’خدا کی قسم جو تم نے بیان کیا عیسٰی اس سے اس تنکے کے برابر زیادہ نہیں۔‘‘
دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ وقت نے خود مخالفِ اسلام مغربی پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ وہ اس طرح کہ صدیوں تک مغرب میں مسلمانوں کو ایک خونخوار وحشی کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا کہ مسلمان بات بات میں مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، فورًا تلوار اٹھا کر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اب قدرت نے کروڑوں مسلمانوں کو مغرب میں پہنچا دیا اور یہاں کے عام آدمی کو روزمرہ کی زندگی میں اس ’’خونخوار‘‘ مسلمان سے سابقہ پڑنے لگا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مسلمان اس پر حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ بہ نسبت گوروں اور کالوں کے زیادہ پرامن طور پر رہتا ہے، اس کا خاندانی نظام خوشگوار حد تک مستحکم ہے، تو وہ اسلام کے متعلق اپنے بڑوں کی غلط بیانی پر سوچنے لگتا ہے، اس طرح بالواسطہ طور پر اسلام کے متعلق بھی غور کرنے لگتا ہے۔ اس موقع پر اگر اسلام کی صحیح اور مثبت فکر پیش کی جائے تو اس کی کامیابی کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں۔
مغرب میں اسلام کو بطور نظریہ و فکر کے پیش کرنے کا یہی سب سے بہترین وقت ہے کہ مغرب میں ایک نظریاتی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ سوویت یونین کا خاتمہ محض ایک فیڈریشن کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نظریہ کی ناکامی کا اعلان تھا۔ کمیونزم ایک نظریہ تھا جس نے بنی آدم کے اجتماعی مسائل کا ایک حل تجویز کیا۔ ستر برس کے تجربہ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ انسان کے مسائل نہ صرف برقرار ہیں بلکہ ان میں اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ اشتراکیت و سرمایہ داری کے اس تصادم میں سرمایہ داری کو ہر طور پر کامیابی ہوئی۔ اس وقت عالمی سطح پر سرمایہ داری کو کوئی نظری چیلنج درپیش نہیں۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے، کسی نظریہ کی بقا کے لیے اس کی ضد کا ہونا ضروری ہے۔ اس بنا پر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سرمایہ داری کو اگر کسی نظری چیلنج کا سامنا ہوا تو اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اس صورت میں اس کے داخلی تضادات سامنے آئیں گے، اور یہ نظریہ خود اپنے ہی وجود میں شکست و ریخت کے عمل سے گزرے گا جو بالآخر اس کی موت پر منتج ہو گا۔ ان کے نزدیک جو نظریہ سرمایہ داری کو چیلنج کر سکتا ہے وہ اسلام ہے، اس لیے کمیونزم کے بعد اسلام کو متوقع خطرہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
مغرب کی ایک اسلام دشمن طاقتور لابی، جو اسلام کے نظریہ کی طاقت سے خوفزدہ ہے، اس کی حکمتِ عملی یہ ہے کہ اسلام کو تہذیبی و سیاسی طور پر مغرب کا حریف بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ اسلام کے خلاف اس حد تک نفرت بڑھ جائے کہ اہلِ مغرب کھلے دل سے اسلام کے نظریہ و فکر پر غور نہ کر سکیں۔ بدقسمتی سے بعض نادان مسلم رہنما جنہوں نے مسلم ممالک میں بھی اسلام کو اپنے حکمرانوں سے ٹکراؤ کا عنوان بنا کر مسلم حکمرانوں کو غیر ضروری طور پر اسلامی تحریکوں کا دشمن بنا دیا ہے، وہ سیاسی طور پر ٹکرا کر مسلم ملکوں میں اسلامی دعوت کے مواقع برباد کر چکے ہیں، یہ لوگ عملاً یہاں مغرب میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے خلافت و جہاد کے نام پر ہنگامے کھڑے کر کے محاذ آرائی شروع کر رکھی ہے۔ غرض دونوں جگہ ان پرجوش مسلم رہنماؤں نے ایک بے فائدہ لڑائی چھیڑی ہوئی ہے۔ ان لڑائیوں نے اسلام کی دعوت و فکر پیش کرنے کے مواقع برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔
دنیا کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے کرنے کا اہم ترین کام صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھیں، علمی و عملی طور پر اس کے نظریہ و فکر کو پیش کریں، اس طرح وہ خدا کی رحمتوں کا سب سے زیادہ حصہ پانے کے حقدار ٹھہریں گے۔ یہی وہ کام ہے جس پر ان کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات وابستہ ہے۔
فریاد نہیں ۔۔۔ دین کی دعوت
ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری
اسلام ایک عالم گیر دین ہے اور اس کی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچنا چاہیے۔ امتِ مسلمہ کا فرض ہے کہ حکمت، دل سوزی اور ہم دردی سے لوگوں کو دعوتِ دین دے۔ جب تک مسلمان دعوت کا کام کرتے رہے، دین کو فروغ حاصل ہوتا رہا اور مسلمانوں کا وقار بڑھتا رہا۔ مگر یہ اسلام کے صدرِ اول کی بات ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دعوتی کام میں کمی آئی اور لوگ دین سے زیادہ دنیا کے کاموں میں لگ گئے۔ انہوں نے دین کو مدرسے والوں کے لیے چھوڑ دیا اور مدرسے والوں کی مالی سرپرستی کو خدمتِ دین کے طور پر کافی سمجھ لیا۔ نتیجتاً دین کی حیثیت ثانوی ہوتی گئی۔ آسودہ حال خاندانوں کے طلباء میڈیکل، انجینئرنگ اور سائنس میں آگے بڑھتے گئے۔ ان حالات نے دین کو بقولِ حالی غریب الغرباء بنا دیا۔
حالات یہاں تک پہنچے کہ موجودہ دور کے مسلمان ایک طرح کے فکری فاقے کا شکار ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ حالات کا واقعاتی تجزیہ تک نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج کل مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف احتجاج کی قسم کی ایک چیز ہے، یا فریاد ہے۔ ہم حالات کا صحیح تجزیہ کر کے کوئی قابلِ عمل اور مفید فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اپنے لیڈروں کے بیانات سنیے، سربراہ کانفرنس کا حال پڑھیے، ان کی سیاسی کوششوں کا تجزیہ کیجیے، تو ایک بات مشترک نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری ساری پریشانیوں کا سبب دوسرے ہیں، ہم نہیں۔ استعماری قوتوں کی سازشیں، غیر قوموں کے مظالم، سرحدوں کے پار والوں کا طرزعمل، بس یہی سب کچھ ہے جو آج ہم جانتے ہیں۔ ہم کبھی خود اپنا احتساب نہیں کرتے۔ میری حقیر رائے میں یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم خود اپنے دشمن بن گئے ہیں۔ حالات سے معقولیت کے ساتھ، مومنانہ فراست کی روشنی میں نمٹنے کی صلاحیت ہم میں باقی نہیں رہی، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔
آدھی صدی پہلے کی بات ہے، امیر شکیب ارسلان مسلمانوں کے ایک رہنما تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ’’لماذا تاخر المسلمون و تقدم غیرھم‘‘ یعنی مسلمانوں کو کس چیز نے پس ماندہ کر دیا اور دوسرے کیسے آگے بڑھ گئے۔ اس میں صرف باہری ہاتھوں سے شکوہ تھا، یہ کہیں نہیں تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارا اندازِ فکر ہی یہ بن گیا ہے کہ ہم حالات سے پریشان تو ہیں مگر ان سے نمٹنے کے امکانات پر غور نہیں کرتے۔ ہم میں مومنانہ فراست کی کمی ہے، ہمارے پاس اللہ کا وہ نور نہیں ہے جس سے ہم حالات سے نمٹنے کی ترکیب دیکھتے۔ ہم معاملے میں عسر اور مشکل کا ادراک تو رکھتے ہیں مگر یسر اور آسانی کو نہیں سمجھ پاتے۔ حالانکہ اللہ تعالٰی کی سنت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی پیدا فرماتے ہیں۔ ضرورت مومنانہ فراست اور مسلمانانہ نظر کی ہوتی ہے۔
اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ حضرت موسٰی اور حضرت ہارون علیہما السلام فرعون کو دعوتِ دین دیتے ہیں، وہ معجزہ طلب کرتا ہے، حضرت موسٰی علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں اور اژدھا بن کر وہ دوڑنے لگتا ہے، فرعون اور اس کے مشیر اسے جادو کا کارنامہ سمجھتے ہیں، حضرت موسٰی علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہیں، حضرت موسٰی علیہ السلام چیلنج قبول کرتے ہیں اور ایک یوم الزینہ (Public holiday) مقابلے کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ فرعون مصر کے سارے جادوگر جمع کر لیتا ہے، یہ لوگ ڈنڈے اور رسیاں ڈال کر انہیں نظربندی کے ذریعے سے سانپ بنا دیتے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت موسٰی علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ارشاد ربانی ہوا کہ ڈرو نہیں، غالب تم ہی رہو گے، اپنے ہاتھ کا عصا تو میدان میں ڈالو، یہ عصا ان کے سارے کھیل کو ختم کر دے گا۔ اور یہی ہوا، حضرت موسٰی علیہ السلام کا عصا کو زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ اژدھا بن کر سارے سانپوں کو کھا گیا۔ (سورہ طہ ۶۶۔۶۹)
آج مسلمان بھی اسی طرح ڈر رہے ہیں۔ سازشوں کے سنپو لیے، غیر ملکی ہاتھوں کے بچھو اور استعماری حکمتِ عملی کے اژدھے انہیں مبہوت کیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بغل کے عصائے کلیمی کو بھول گئے ہیں اور ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں۔ آج اسلام کی تعلیمات علم و سائنس کی روشنی میں اپنی صداقت کا لوہا منوا رہی ہیں، غیر مسلم بھی اب اسلام کے بارے میں حقیقت پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ نئے مؤرخ اسلام کی صحیح تاریخ لکھ رہے ہیں۔ اہلِ کتاب اسلام کو سمجھ کر اسلام کے قریب آنے کی کوشش میں بین المذاہب مکالمات کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ پوپ نے نئے منشور میں مسلمان کو نجات کا مستحق مان لیا ہے، وہ اب مسلمانوں کو خارج از دین نہیں سمجھتے۔ کمیونزم اپنی موت مر گیا، روس میں مسلمانوں کو تحفظ ملا ہے۔ دنیا کی ساری مشہور تعلیم گاہوں نے اسلامیات کے شعبے کھولے ہیں جہاں تحقیقی کام ہو رہا ہے۔ قدیم عربی و اسلامی لٹریچر شائع ہو رہا ہے۔
غرض الحمد للہ مختلف عالمی دباؤ کے تحت اسلام کے حق میں ایک اعتدال کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ مناظرہ بازی کا دور ختم ہوا، اب ڈائیلاگ کا دور آ گیا ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ اپنی تعلیمات پیش کرتے ہیں اور دوسرے کی بات غور سے سن کر تعاون کے امکانات پر غور کرتے ہیں۔ خود یہ فقیر ایسے بہت سے ڈائیلاگز میں شریک رہا ہے۔ ’’نیشنل کانفرنس آف جیوز اینڈ کرسچینز‘‘ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے خاص تھی، اب حالات کے اثر اور ہم فقیروں کی کوششوں سے صرف ’’نیشنل کانفرنس‘‘ بن گئی ہے، اب اس میں ہر مذہب کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلام کے حق میں ہیں۔
اب ہم کلیساؤں (Churches)، صومعوں (Synagogues) تک میں جا کر اسلام کا عالمی پیغامِ امن دے سکتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائی ہوئی افواہوں اور الزامات کا معقول علمی جواب دے سکتے ہیں۔ پہلے جو کام دشمنی کے ماحول میں مناظرانہ انداز میں ہوتا تھا، اب دوستی کے ماحول میں افہام و تفہیم کے انداز میں ہو رہا ہے۔ اب یہ خیال نہیں ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی دعوت کے زبردست امکانات کھل گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالٰی کے منصوبہ کمال کا فضل ہے کہ اب مخالفت، دشمنی اور اذیت رسانی کے خوف کے بغیر ہم تبلیغِ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالٰی کا مخصوص انعام ہے کہ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف ممالک میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں تامل ناڈو اور دوسری ریاستوں میں لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی سازشیں انہیں روک نہیں پا رہی ہیں۔ افریقی ممالک میں دین تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فرانس میں دین تیزی سے پھیل رہا ہے، فرانس میں کیتھولک عیسائیوں کے بعد مسلمان سب سے بڑی تعداد میں ہیں۔ یورپ کے اندر ایک مسلمان ریاست بوسنیا وجود میں آ گئی ہے۔ جرمنی میں لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے ہیں۔ برطانیہ، جاپان اور امریکہ میں ہر جگہ سے لوگوں کے قبولِ اسلام کی خبریں آ رہی ہیں۔ روم میں، جو اسلام دشمنی کا مرکز تھا، ایک عظیم الشان مسجد اور سنٹر کھل گیا ہے۔ اسپین میں مسلمان بڑھ رہے ہیں، غرناطہ میں بہت بڑا اسلامی مرکز بن گیا ہے، اب اسپین کے ہر شہر میں مسلمان نظر آتے ہیں۔
غرض آج اسلام ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ ہم ایک داعی امت ہیں، ہمیں اپنا منصب پہچاننا چاہیے اور اندرونی اختلافات کو بھلا کر دعوتِ دین کے کام میں لگ جانا چاہیے۔
(بشکریہ: ماہنامہ بزمِ قاسمی، کراچی)
تفسیرِ کبیر اور اس کی خصوصیات
محمد عمار خان ناصر
’’مفاتیح الغیب‘‘ یعنی تفسیر کبیر کا شمار تفسیر بالرائے کے طریقہ پر لکھی گئی اہم ترین تفاسیر میں ہوتا ہے۔ اس کی تصنیف چھٹی صدی ہجری کے نامور عالم اور متکلم امام محمد فخر الدین رازیؒ (۵۴۳ھ ۔ ۶۰۶ھ) نے شروع کی لیکن اس کی تکمیل سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں اس کی تکمیل حاجی خلیفہؒ کی رائے کے مطابق قاضی شہاب الدین بن خلیل الخولی الدمشقیؒ نے، اور ابن حجرؒ کی رائے کے مطابق شیخ نجم الدین احمد بن محمد القمولیؒ نے کی۔ یہ بات بھی معیّن طور پر معلوم نہیں کہ تفسیر کا کتنا حصہ خود امام صاحبؒ لکھ پائے تھے۔ ایک قول کے مطابق سورۃ الانبیاء تک جبکہ دوسرے قول کے مطابق سورۃ الفتح تک تفسیر امام صاحبؒ کی اپنی لکھی ہوئی ہے(۱)۔ تاہم اس معاملے میں سب سے زیادہ تشفی بخش اور مدلل نقطۂ نظر الاستاذ عبد الرحمٰن المعلی نے اپنے مضمون ’’حول تفسیر الفخر الرازی‘‘ میں اختیار کیا ہے۔ انہوں نے مضبوط داخلی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ تفسیر کے درج ذیل حصے خود امام صاحبؒ نے لکھے ہیں جبکہ باقی اجزاء الخولیؒ یا القمولیؒ کے لکھے ہوئے ہیں:
۱۔ سورۂ فاتحہ سے سورۂ قصص تک
۲۔ سورۂ صافات سے سورۂ احقاف تک
۳۔ سورۂ حشر، مجادلہ اور حدید
۴۔ سورۂ ملک سے آخر قرآن تک (۲)
تفسیر کی خوبیاں
(۱) جامعیت
تفسیر کبیر کی نمایاں ترین خصوصیت، جس کا اعتراف اکابر اہلِ علم نے کیا ہے، اس کی جامعیت ہے۔ وہ جس مسئلہ پر لکھتے ہیں، اس کے متعلق جس قدر مباحث ان سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، ان سب کا استقصا کر دیتے ہیں۔ محمد حسین ذہبیؒ لکھتے ہیں:
’’رازی کی تفسیر کو علما کے ہاں عام شہرت حاصل ہے کیونکہ دوسری کتبِ تفسیر کے مقابلے میں اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں مختلف علوم سے متعلق وسیع اور بھرپور بحثیں ملتی ہیں۔‘‘ (۳)
علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں:
’’قرآن کریم کے مشکلات میں مجھے کوئی مشکل ایسی نہیں ملی جس سے امام رازیؒ نے تعرض نہ کیا ہو، یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات مشکلات کا حل ایسا پیش نہیں کر سکے جس پر دل مطمئن ہو جائے۔‘‘(۴)
ہر آیت کی تفسیر میں امام صاحبؒ کا طریقہ حسبِ ذیل ہے:
(۱) آیت کی تفسیر، نحوی ترکیب، وجوہِ بلاغت اور شانِ نزول سے متعلق سلف کے تمام اقوال نہایت مرتب اور منضبط انداز میں پوری شرح و وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔
(۲) آیت سے متعلق فقہی احکام کا ذکر تفصیلی دلائل سے کرتے ہیں اور امام شافعیؒ کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں۔
(۳) متعلقہ آیات کے تحت مختلف باطل فرقوں مثلاً جہمیہ، معتزلہ، مجسمہ وغیرہ کا استدلال تفصیل سے ذکر کر کے اس کی تردید کرتے ہیں۔
ان میں سے پہلے دو امور کا ذکر اگرچہ دوسرے اہلِ تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن یہ ذخیرہ ان میں منتشر اور بکھرا ہوا ہے، جبکہ تفسیر کبیر میں یہ تمام مباحث یکجا مل جاتے ہیں۔ البتہ تیسرے امر کے اعتبار سے تفسیر کبیر اپنی نوعیت کی منفرد تفسیر ہے۔
(۲) ترجیح و محاکمہ
امام صاحبؒ نے اپنی تفسیر میں جمع اقوال پر اکتفا نہیں کی بلکہ دلائل کے ساتھ بعض اقوال کو ترجیح دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، جس سے تفسیر کے متعلقہ علوم و فنون میں ان کی دسترس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر گویا سابقہ تفسیری ذخیرے پر ایک محاکمہ کا درجہ رکھتی ہے۔
مختلف تفسیری اقوال میں ترجیح قائم کرتے ہوئے امام صاحبؒ بالعموم حسبِ ذیل اصول پیشِ نظر رکھتے ہیں:
(۱) اگر کسی قول کی تائید میں صحیح حدیث موجود ہو تو اس کو ترجیح دیتے ہیں۔
وَنُفِخَ فیِ الصُّوْرِ کی تفسیر میں تین اقوال نقل کرتے ہیں: ایک یہ کہ صور ایک آلہ ہے، جب اس کو پھونکا جائے گا تو ایک بلند آواز پیدا ہو گی جس کو خداوند تعالٰی نے دنیا کی بربادی اور اعادۂ اموات کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ لفظ بفتح الواو ہے اور صورۃ کی جمع ہے۔ مراد یہ ہے کہ ’’جب صورتوں میں روح پھونکی جائے گی‘‘۔ تیسرا یہ کہ یہ ایک استعارہ ہے جس کا مقصد مُردوں کا اٹھانا اور ان کو جمع کرنا ہے۔ امام رازیؒ نے ان اقوال میں سے پہلے قول کو اس بنا پر ترجیح دی ہے کہ اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے(۵)۔
(۲) جو مفہوم عقل کے مطابق ہو، اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔
سورۂ نساء کی آیت خَلَقُکْم مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَۃٍ وَّخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا کی تفسیر میں عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت حوا علیہا السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور اس کی تائید میں حدیث بھی موجود ہے۔ لیکن امام رازیؒ ابو مسلمؒ کی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں جن کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی جنس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ امام صاحبؒ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالٰی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر سکتے تھے، اسی طرح حضرت حوا علیہا السلام کو بھی کر سکتے تھے، پھر ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کرنے میں کا فائدہ؟(۶)
اسی طرح سورۂ کہف میں ذوالقرنین کے قصہ میں ارشاد باری ہے:
حَتّٰی اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تَغْرُبُ فِیْ عَیْنٍ حَمِئَۃٍ۔
’’یہاں تک کہ جب وہ آفتاب کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو سورج کو کیچڑ کی ایک نہر میں ڈوبتے دیکھا‘‘(۷)۔
اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ سورج درحقیقت کیچڑ میں ڈوبتا ہے۔ لیکن امام رازیؒ کے نزدیک یہ تفسیر بالکل خلافِ عقل ہے کیونکہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے اس لیے وہ زمین کی کسی نہر میں کیسے ڈوب سکتا ہے؟(۸)
(۳) جب تک کسی لفظ کا حقیقی اور معروف معنی مراد لینا ممکن ہو، اس وقت تک اس کا مجازی یا غیر معروف معنی مراد نہیں لیتے۔
مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں وَفَارَ التَّنُّوْر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لفظ تنور کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں: ایک یہ کہ اس سے مراد وہی تنور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد سطح زمین ہے۔ تیسرا یہ کہ اس سے مراد زمین کا بلند حصہ ہے۔ چوتھا یہ کہ اس سے مراد طلوعِ صبح ہے۔ پانچواں یہ کہ یہ محاورتاً واقعہ کی شدت کی تعبیر ہے۔ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد امام رازیؒ لکھتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کلام کو حقیقی معنی پر محمول کرنا چاہیے اور حقیقی معنی کے لحاظ سے تنور اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں روٹی پکائی جاتی ہے۔(۹)
اسی طرح وَمَنْ یَّغْلُلْ یَاْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ (جس نے مال غنیمت میں خیانت کی وہ اس مال کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا) کی تفسیر میں دو قول نقل کرتے ہیں: ایک یہ کہ حقیقتاً ایسا ہی ہو گا۔ دوسرا یہ کہ اس تعبیر سے محض عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ علمِ قرآن میں جو اصول معتبر ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر قائم رکھنا چاہیے اِلّا یہ کہ کوئی اور دلیل اس سے مانع ہو۔ یہاں چونکہ ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی مانع نہیں اس لیے اسی کو قائم رکھنا چاہیے۔(۱۰)
(۴) اس قول کو مختار قرار دیتے ہیں جو کلام کی نحوی ترکیب کی وجوہ میں سے بہتر وجہ کے مطابق ہو۔
سورہ بقرہ کی آیت وَلٰکِنَّ الشَّیَاطِیْنَ کَفَرُوْا یُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السَِّحْرَ وَمَا اُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ مَا اُنْزِلَ میں مَا نافیہ ہے یا موصولہ۔ نیز اس کا عطف السِّحْر پر ہے یا مَا تَتْلُوا الشَّیَاطِیْنُ پر۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ مَا کو موصولہ قرار دینا اور اس کا عطف السِّحْر پر کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو لفظ قریب ہے اس پر عطف کرنا بعید لفظ پر عطف کرنے سے زیادہ مستحسن ہے۔(۱۱)
(۳) آیات و سور میں باہمی ربط
امام رازیؒ قرآن مجید میں نظم کے قائل ہیں اور اپنی تفسیر میں آیات اور سورتوں کا باہمی ربط نہایت اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں دو رائیں ہیں۔ مولانا تقی عثمانی کا خیال یہ ہے کہ
’’آیتوں کے درمیان ربط و مناسبت کی جو وجہ وہ بیان فرماتے ہیں وہ عموماً اتنی بے تکلف، دل نشین اور معقول ہوتی ہے کہ اس پر دل نہ صرف مطمئن ہو جاتا ہے بلکہ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا غیر معمولی تاثر پیدا ہوتا ہے۔‘‘(۱۲)
جبکہ مولانا امین احسن اصلاحیؒ فرماتے ہیں کہ
’’اس سلسلے میں ان کی کوششیں کچھ زیادہ مفید ثابت نہیں ہوئیں کیونکہ نظمِ قرآن کھولنے کے لیے جو محنت درکار تھی اس کے لیے ان کے جیسے مصروف مصنف کے پاس فرصت مفقود تھی۔‘‘(۱۳)
تاہم اصولی طور پر امام رازیؒ نظم کی رعایت پر نہایت شدت سے اصرار کرتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ حم السجدہ کی آیت وَلَوْ جَعَلْنَاہُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِیًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰیَاتُہٗ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
نقلوا فی سبب نزول ھذہ الایۃ ان الکفار لاحل التعنت قالوا لو نزل القرآن بلغۃ العجم فنزلت ھذہ الآیۃ و عندی ان امثال ھذہ الکلمات فیھا حیف عظیم علی القرآن لانہ یقتضی ورود آیات لا تعلق للبعض فیھا بالبعض۔ وانہ یوجب اعظم انواع الطعن فکیف یتم مع التزام مثل ھذا الطعن ادعاء کونہ کتابا منتظما فضلا عن ادعاء کونہ معجزا؟ بل الحق عندی ان ھذہ السورۃ من اولھا الی آخرھا کلام واحد۔
’’لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں اتری ہے جو ازراہِ شرارت یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کسی عجمی زبان میں اتارا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن اس طرح کی باتیں کہنا میرے نزدیک کتابِ الٰہی پر سخت ظلم ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ قرآن کی آیتوں میں باہم دگر کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، حالانکہ یہ کہنا قرآن حکیم پر بہت بڑا اعتراض کرنا ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کو معجزہ ماننا تو الگ رہا، اس کو ایک مرتب کتاب کہنا بھی مشکل ہے۔ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ شروع سے لے کر آخر تک ایک مربوط کلام ہے۔‘‘
اس کے بعد اس آیت کی تفسیر لکھ کر فرماتے ہیں:
وکل من انصف ولم یتعسف علم انا اذا فسرنا ھذہ الآیۃ علی الوجہ الذی ذکرنا صارت ھذہ السورۃ من اولھا الٰی آخرھا کلاما واحد منتظما مسوقا نحو غرض واحد۔
’’ہر منصف جو انکارِ حق کا عادی نہیں ہے، تسلیم کرے گا کہ اگر سورہ کی تفسیر اس طرح کی جائے جس طرح ہم نے کی ہے تو پوری سورہ ایک ہی مضمون کی حامل نظر آئے گی اور اس کی تمام آیتیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کریں گی۔‘‘(۱۴)
(۴) عقلی انداز
امام رازیؒ اپنے زمانے کے عقلی اور فلسفیانہ علوم کے بلند پایہ عالم تھے۔ مسلمانوں کے مابین پیدا ہونے والے کلامی اختلافات اور ان کی مذہبی و عقلی بنیادوں پر ان کی گہری نظر تھی، اور اسلام کے مختلف مسائل پر یونانی فلسفہ کے زیراثر پیدا ہونے والے اعتراضات سے بھی وہ پوری طرح آگاہ تھے۔ چنانچہ قدرتی طور پر ان کی تفسیر پر عقلی رنگ غالب ہے اور ان کی بحثوں میں ان تمام علوم کی بھرپور جھلک دکھائی دیتی ہے جن کے مطالعہ کا موقع امام صاحبؒ کو میسر آیا تھا۔ تفسیر کبیر میں اس عقلی ذوق کا اظہار حسبِ ذیل صورتوں میں ہوا ہے:
اسلامی عقائد کی براہین و دلائل سے تائید
امام صاحبؒ نہ صرف اسلامی عقائد کا دفاع بڑی حمیت اور جوش سے کرتے ہیں بلکہ اس سلسلے میں معذرت خواہانہ رویہ کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت ۱۲ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنّات کو مسخر کر دیا۔ بعض لوگوں نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ ہوا سے مراد تیز رفتار گھوڑے اور جنّات سے مراد طاقتور انسان ہیں۔ امام رازیؒ یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں:
وھذا کلہ فاسد حملہ علٰی ھذا ضعف اعتقادہ و عدم اعتمادہ علٰی قدرۃ اللّٰہ واللّٰہ قادر علٰی کل ممکن وھذہ اشیاء ممکنۃ۔
’’یہ بات بالکل غلط ہے، کہنے والے نے اس لیے کہی ہے کہ اس کا اعتقاد کمزور ہے اور اسے اللہ کی قدرت پر اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تعالٰی ہر ممکن پر قادر ہیں اور یہ باتیں بھی ممکنات میں سے ہیں۔‘‘(۱۵)
اسلامی فرقوں کے کلامی جھگڑے
کلامی اختلافات امام صاحبؒ کی دلچسپی کا خاص موضوع ہیں اور وہ موقع بموقع معتزلہ اور اشاعرہ کے مابین نزاعی مسائل پر بحثیں کرتے ہیں۔ امام صاحبؒ اشاعرہ کے گرم جوش ترجمان ہیں اور، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں گے، ان کی حمایت میں حدود سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں۔
دینی حقائق کی عقلی تعبیر
امام صاحبؒ کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی آیات جن میں ماوراء العقل حقائق کا اظہار کیا گیا ہو، عام طریقے سے ان کی تفسیر کرنے کے بعد ان کی فلسفیانہ تعبیر بھی پیش کرتے ہیں۔
ملحدین کے اعتراضات کے جوابات
تفسیر کبیر میں قرآنی مضامین پر ملحدین کے اعتراضات سے بکثرت تعرض کیا گیا ہے۔ ان کے جواب میں امام صاحبؒ یا تو مناظرانہ انداز میں ان کی تردید کرتے ہیں، یا آیات کی توجیہ و تاویل کر کے ان کا صحیح مفہوم واضح کرتے ہیں۔
احکامِ شریعت کے اسرار
تفسیرِ کبیر میں بہت سے مقامات پر شرعی احکام کے اسرار اور ان کی حکمتیں بھی زیربحث آئی ہیں۔ کتاب کے عمومی مزاج کے تحت ان کی توضیح میں بھی فلسفیانہ ذوق غالب ہے۔
(۵) اسرائیلیات سے متعلق محتاط رویہ
تفسیر بالروایت کے طریقے پر لکھی گئی کتبِ تفسیر میں ایک بڑا حصہ اسرائیلی روایات کا ہے۔ قرآن مجید میں اممِ سابقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے جن واقعات و احوال کا اجمالاً تذکرہ ہوا ہے، ان کی تفصیلات مہیا کرنے کے شوق میں غیر محتاط مفسرین نے بے سروپا روایات کا ایک انبار لگا دیا ہے۔ یہ روایات بالعموم روایت کے معیار کے لحاظ سے ناقابلِ استناد اور عقل و درایت کے اعتبار سے بالکل بے تکی ہیں۔ اسی لیے محقق مفسرین نے ان کو اپنی تفسیروں میں جگہ دینے سے گریز کیا ہے۔ امام رازیؒ کا طریقہ بھی اس سلسلے میں احتیاط پر مبنی ہے۔
اسرائیلی روایات درحقیقت دو طرح کی ہیں:
(۱) بعض ایسی ہیں کہ ان میں وارد تفصیلات قرآن و سنت کے مسلّمات سے تو نہیں ٹکراتیں لیکن فہمِ قرآن کے حوالے سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں امام رازیؒ ان کو نقل تو کرتے ہیں لیکن ان کی تردید یا تائید کیے بغیر یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ان سے اعتنا کرنا ایک بے کار کام ہے کیونکہ یہ تفسیر کے اصل مقصد کے لحاظ سے کارآمد نہیں ہیں۔
مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اس کی تعیین میں تفسیری روایات مختلف ہیں۔ بعض کے مطابق یہ گیہوں کا درخت تھا، بعض کے نزدیک انگور اور بعض کے ہاں انجیر کا۔ امام رازیؒ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے اس درخت کی تعیین نہیں ہوتی اس لیے ہم کو بھی اس تعیین کی ضرورت نہیں کیونکہ اس قصہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کو متعین طور پر اس درخت کا علم ہو۔ جو چیز کلام کا اصل مقصود نہیں ہوتی اس کی توضیح بعض اوقات غیر ضروری ہوتی ہے۔(۱۶)
قرآن مجید میں مذکور قیامت کی علامات میں ایک علامت ’’دابۃ الارض‘‘ کا نکلنا بھی ہے۔ مفسرین نے اس جانور کے حجم، اس کی خلقت اور اس کے نکلنے کے طریقے کے متعلق بے شمار روایات اکٹھی کی ہیں، لیکن امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اگر ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی ہو تو وہ قبول کر لی جائے گی ورنہ وہ ناقابلِ التفات قرار پائے گی۔(۱۷)
اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ساخت اور اس کی لمبائی چوڑائی کے متعلق مختلف تفسیری اقوال نقل کر کے لکھتے ہیں:
’’اس قسم کی بحثیں مجھے اچھی نہیں لگتیں کیونکہ ان کا علم غیر ضروری ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اور ان میں غور و فکر کرنا فضول ہے، بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ ہم کو یقین ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو صحیح جانب پر دلالت کرے۔‘‘(۱۸)
(۲) دوسری قسم ان روایات کی ہے جو قرآن و سنت کے مسلّمات کے صریح معارض اور ان کی بنیاد کو ڈھا دینے والی ہیں۔ ایسی روایات بالعموم بعض انبیاء سابقین کے واقعات کے تحت نقل کی ہوئی ہیں۔ تمام محقق مفسرین نے ان کی تردید کی ہے، چنانچہ امام رازیؒ نے بھی حسبِ ذیل روایات کو بے اصل قرار دیا ہے:
۱۔ واقعہ ہاروت و ماروت کے ضمن میں مروی روایات، جن کے مطابق یہ دونوں فرشتے تھے جو زمین پر بھیجے گئے اور ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی خواہش میں بت پرستی، شراب نوشی اور قتل کے مرتکب ہوئے۔(۱۹)
۲۔ سورہ اعراف کی آیت ۲۴ کے الفاظ فَلَمَّا اٰتَاھُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَہٗ شُرْکَآءَ فِیْ مَآ اٰتَاھُمَا کے تحت مروی آیت جس میں ذکر ہے کہ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کا ذکر ہے جنہوں نے ابلیس کے ورغلانے میں آ کر اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔(۲۰)
۳۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں مروی روایت جس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام آمادۂ گناہ ہو گئے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے ان کو دھکیل کر ہٹایا اور وہ بالکل ناکارہ ہو گئے۔(۲۱)
۴۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کے تحت مروی روایات جن کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اوریا کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے اور اس کے خاوند کو قتل کرا کے اس سے نکاح کر لیا۔(۲۲)
تفسیر کبیر پر اعتراضات
اپنی تمام تر افادیت اور خوبیوں کے باوجود تفسیر کبیر خامیوں سے پاک نہیں۔ ہم ذیل میں ان چند امور کا ذکر کرتے ہیں جن پر اہلِ علم نے اعتراض کیا ہے۔
(۱) غیر متعلق مباحث کی کثرت
تفسیر کبیر کے ایسے عقلی مباحث جن سے منصوصات کی تائید یا ان کی تفہیم میں مدد ملتی ہے، ان کی تمام منصف مزاج اہلِ علم نے قدر کی ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ اس تفسیر میں ایک بڑا ذخیرہ ایسے فنی مباحث کا بھی ہے جن کا قرآن کی تاویل و تشریح سے کوئی تعلق نہیں، اور جنہیں امام صاحبؒ نے محض اپنے عقلی ذوق کی تشفی کے لیے تفسیر کا حصہ بنا دیا ہے۔ محمد حسین ذہبیؒ لکھتے ہیں:
’’تفسیر دیکھنے سے ظاہر ہے کہ امام رازی کو زیادہ سے زیادہ نکتے استنباط کرنے اور دائرۂ گفتگو کو وسیع سے وسیع تر کرنے کا ازحد شوق ہے۔ قرآن کے الفاظ سے کسی موضوع کا ذرا بھی تعلق نظر آئے تو وہ اس کو دائرۂ بحث میں لے آتے اور اس سے متعلق نکات استنباط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔‘‘(۲۳)
تفسیر کے مقدمہ میں خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ سورہ فاتحہ سے دس ہزار فوائد اور نکات استنباط کیے جا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کو ناممکن قرار دیا۔ چنانچہ میں نے اس بات کو ممکن الحصول ثابت کرنے کے لیے فاتحہ کی تفسیر میں اس قدر تطویل سے کام لیا ہے(۲۴)۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں سورۂ فاتحہ کی تفسیر ۲۹۰ صفحات کو محیط ہے۔ اس ذوق کا نتیجہ یہ ہے کہ کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ ریاضی، طبیعیات، ہیئت، فلکیات، فلسفہ اور علمِ کلام کے طویل مباحث کی نذر کر دیا گیا ہے۔ تفسیر کبیر کا یہ پہلو غالباً تمام اہلِ علم کی نظر میں کھٹکا ہے اور اس حوالے سے اس پر تنقید کی گئی ہے۔ سیوطیؒ لکھتے ہیں:
’’صاحبِ علومِ عقلیہ بالخصوص امام رازی نے اپنی تفسیر کو حکما، فلاسفہ اور ان جیسے لوگوں کے اقوال سے بھر دیا اور ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف اس طرح نکل گئے کہ دیکھنے والا تعجب کرتا ہے کہ آیت کے موقع و محل سے اس کو کیا مطابقت ہے؟ ابو حیان بحر میں لکھتے ہیں کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں بہت سی طویل چیزوں کو جمع کر دیا ہے جن کی ضرورت علمِ تفسیر میں نہیں، اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ تفسیر کبیر میں ہر چیز ہے، صرف ایک تفسیر نہیں ہے‘‘۔(۲۵)
الدکتور محمد حسین ذہبیؒ بھی اس کی تائید کرتے ہیں:
’’خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کتاب کو علمِ کلام اور طبیعی و کائناتی علوم کا انسائیکلو پیڈیا کہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ پہلو اس پر اس قدر غالب ہے کہ اس کی تفسیر ہونے کی حیثیت دب کر رہ گئی ہے‘‘۔(۲۶)
(۲) متکلمانہ جانبداری
تفسیر کبیر پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس میں امام صاحبؒ نے کلامی جھگڑوں کے حوالے سے ایک خاص نقطۂ نظر کی وکالت کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحیؒ کی رائے حسبِ ذیل ہے:
’’مسلمانوں کا تعلق جب عجمی قوموں سے ہوا اور ان کے علوم اور ان کے فلاسفہ سے ان کو سابقہ پڑا تو دینی مسائل پر سوچنے کا وہ اندازِ فکر وجود میں آیا جس کا ہم علمِ کلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس علمِ کلام نے بھی ہمارے اندر مختلف مکتبِ خیال پیدا کیے اور ان میں سے ہر مکتبِ خیال کے لوگوں نے اپنے مخصوص افکار و نظریات کو مسلمانوں میں مقبول بنانے کے لیے قرآن مجید کی تفسیریں لکھیں۔ ان تفسیروں کا مقصد درحقیقت قرآن مجید کی تفسیر لکھنے سے زیادہ ان افکار و نظریات کے دلائل فراہم کرنا تھا جو ان تفسیروں کے لکھنے والوں نے اپنے متکلمانہ طرزِ فکر سے پیدا کیے تھے۔ اس طرز پر ہمارے ہاں جو تفسیریں لکھی گئیں ان میں سب سے زیادہ مشہور اور اہمیت رکھنے والی تفسیریں دو ہیں: ایک علامہ زمحشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کشاف، اور دوسری امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر۔ ان میں سے مقدم الذکر معتزلہ کے مکتبِ خیال کے ترجمان ہیں اور مؤخر الذکر اپنی تفسیر میں ہر جگہ اشاعرہ کے نظریات کی وکالت کرتے ہیں‘‘۔(۲۷)
اشعریت کی حمایت میں امام رازیؒ کے اس غلو کی شکایت علامہ شبلی نعمانیؒ نے بھی کی ہے:
’’امام صاحب نے علمِ کلام کی بنیاد اشاعرہ کے عقائد پر قائم کی اور اس سینہ زوری سے اس کی حمایت کی کہ اشاعرہ کے جو مسائل تاویل کے محتاج تھے ان میں تاویل کا سہارا بھی نہ رکھا اور پھر ان کی صحت پر سینکڑوں دلیلیں قائم کیں۔ مثلاً اشاعرہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان اپنے افعال پر قدرتِ موثرہ نہیں رکھتا تاہم جبر سے بچنے کے لیے انہوں نے کسب کا پردہ لگا رکھا تھا۔ امام صاحب نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا اور صاف صاف جبر کا دعوٰی کیا، چنانچہ تفسیر کبیر میں جابجا اس دعوے کی تصریح کی ہے اور اس پر دلیلیں قائم کی ہیں۔ اسی طرح خدا کے افعال کا بغیر کسی مصلحت و حکمت کے ہونا، حسن و قبح کا عقلی نہ ہونا، زندگی کے لیے جسم کا مشروط نہ ہونا، دیکھنے کے لیے لون و جسم و جہت کا مشروط نہ ہونا، کسی شے میں کسی خاصیت کا نہ ہونا، اشیاء میں سبب و مسبب کا سلسلہ نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مسائل پر سینکڑوں دلیلیں قائم کیں اور انہی مسائل کو اعتزال اور سنیت کا معیار قرار دیا۔ چنانچہ ان کی تمام کتبِ کلامیہ اور تفسیر کبیر انہی مباحث سے بھری پڑی ہیں‘‘۔(۲۸)
ایک مثال سے امام رازیؒ کے اس طرزِ فکر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے:
امام رازیؒ اور تمام اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالٰی بندوں کو تکلیف مالایطاق دیتا ہے یعنی ان پر ایسا بوجھ ڈالتا ہے جس کو اٹھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر انہوں نے اپنی تفسیر میں مختلف آیات کے ذیل میں متعدد دلیلیں بیان کی ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ کی آخری آیت واضح طور پر ان کے اس مسلک کی تردید کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے:
لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَھَا۔
’’اللہ تعالٰی کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔‘‘
اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے متعدد تاویلات سے آیت کے واضح مفہوم کو پلٹنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے دوسری جگہ ایک عجیب دلیل دیتے ہوئے آیت کے ظاہری مفہوم کو رد کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں:
واذا کنت المسئلہ قطعیۃ یقینیۃ کان القول فیھا بالدلائل الظنیۃ الضعیفۃ غیر جائز۔ مثالہ قال اللّٰہ تعالٰی ’’لا یکلف اللّٰہ نفسا الّا وسعھا‘‘ قام الدلیل القاطع علی ان مثل ھذا التکلیف قد وجد علی ما بینا بالبراھین الخمسۃ فی تفسیر ھذہ الآیۃ فعلمنا ان المراد اللّٰہ تعالٰی لیس ما یدل علیہ ظاھر الآیۃ۔
’’جب ایک مسئلہ اپنی جگہ پر قطعی یقینی ہو تو اس کے بارے میں ظنی اور کمزور دلائل کی بنا پر کچھ کہنا ناجائز ہے۔ مثلاً لا یکلف اللّٰہ نفسا الا وسعھا کے متعلق قطعی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس قسم کی تکلیف مالایطاق اللہ تعالٰی اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ہم اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس کی تائید میں پانچ نہایت محکم دلیلیں لکھ چکے ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالٰی کی مراد وہ نہیں ہو سکتی جو ظاہر آیت سے معلوم ہوتی ہے‘‘۔(۲۹)
(۳) اہل السنۃ کی کمزور ترجمانی
بعض علما کی رائے یہ ہے کہ تفسیر کبیر میں باطل فرقوں کا استدلال تو نہایت بھرپور طریقے سے پیش کیا گیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اہلِ سنت کی ترجمانی کمزور طریقے سے کی گئی ہے۔ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:
’’ان پر یہ اعتراض ہے کہ قوی شبہات پیش کرتے ہیں لیکن ان کا تسلی بخش جواب دینے سے عاجز رہ جاتے ہیں، چنانچہ مغرب کے بعض علما نے کہا کہ ان کے اعتراضات نقد ہوتے ہیں اور جواب ادھار۔ شیخ سراج الدین ان پر سخت اعتراض کرتے اور کہتے تھے کہ دین کے مخالفین کے اعتراضات تو نہایت قوت اور زور سے بیان کرتے ہیں لیکن اہلِ سنت کی ترجمانی نہایت کمزور طریقے سے کرتے ہیں‘‘۔(۳۰)
مخالف کے استدلال کو پوری قوت سے پیش کرنے کی عادت کا خود امام رازیؒ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ’’نہایۃ العقول‘‘ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ وہ مخالف کے استدلال کو اس عمدگی سے پیش کریں گے کہ اگر مخالف خود بھی چاہے تو اس سے اچھے طریقے سے پیش نہ کر سکے گا۔(۳۱)
حواشی
- محمد حسین الذہبی: التفسیر والمفسرون ج ۱ ص ۲۹۱۔ محمد تقی عثمانی: علوم القرآن ص ۵۰۴
- ضیاء الدین اصلاحی: ’تفسیر کبیر اور اس کا تکملہ‘، مشمولہ ’ایضاح القرآن‘ ص ۲۰۶ تا ۲۴۸
- التفسیر والمفسرون: ج ۱ ص ۲۹۳
- محمد یوسف بنوری: یتیمۃ البیان مقدمہ مشکلات القرآن ص ۲۳
- فخر الدین الرازی: التفسیر الکبیر ج ۲۴ ص ۲۲۰
- المرجع السابق: ج ۹ ص ۱۶۱
- سورۃ النساء آیت ۱
- التفسیر الکبیر: ج ۲۱ ص ۱۶۷
- المرجع السابق: ج ۱۷ ص ۲۲۶
- المرجع السابق: ج ۹ ص ۷۳
- المرجع السابق: ج ۳ ص ۲۱۸
- علوم القرآن: ص ۵۰۴
- امین احسن اصلاحی: مبادی تدبر قرآن: ص ۱۹۷
- التفسیر الکبیر: ج ۲۷ ص ۱۳۳
- نفس المصدر: ج ۲۵ ص ۲۴۷
- نفس المصدر: ج ۳ ص ۵
- نفس المصدر: ج ۲۴ ص ۲۱۸
- نفس المصدر: ج ۱۷ ص ۲۲۴
- نفس المصدر: ج ۳ ص ۲۱۹
- نفس المصدر:ج ۱۴ ص ۸۶
- نفس المصدر:ج ۱۸ ص ۱۳۰
- نفس المصدر:ج ۲۶ ص ۱۹۲
- التفسیر والمفسرون: ج ۱ ص ۲۹۶
- التفسیر الکبیر: ج ۱ ص ۳
- جلال الدین السیوطی: الاتقان: ج ۲ ص ۱۹۰
- التفسیر والمفسرون: ج ۱ ص ۲۹۵
- مبادی تدبر قرآن: ص ۱۸۵
- شبلی نعمانی: الکلام: ص ۶۳
- التفسیر الکبیر: ج ص
- التفسیر والمفسرون: ج ۱ ص ۲۹۵
- المرجع السابق
امریکی اِکسپوژر کی نئی جہتیں
پروفیسر میاں انعام الرحمن
جمہوریت کے مسلّمہ اصولوں کے مطابق حقیقی جمہوریت اپوزیشن کی موجودگی سے مشروط ہے۔ کمیونسٹ ممالک پر اسی حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے کہ ان کے ہاں اپوزیشن مفقود ہے کیونکہ ان کے ہاں کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کسی دوسری پارٹی کو سیاسی عمل میں شریک نہیں کیا جاتا، لہٰذا حقیقی جمہوریت کے لیے کم از کم دو جماعتی نظام نہایت ضروری ہے۔
دوسری جنگِ عظیم کے بعد سرد جنگ کے دوران اور تاحال امریکہ جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کا سرخیل ہے اور وہاں دو جماعتی نظام رائج ہے۔ برطانیہ میں بھی دو جماعتی نظام رائج ہے لیکن ایسا نہیں کہ دوسری جماعت تقریباً برائے نام یا غیر مؤثر ہو کیونکہ اس طرح بھی جمہوری سپرٹ پیدا نہیں ہوتی۔ دونوں جماعتیں، جو حزب انتشار اور حزب اختلاف کے طور پر ابھریں، متوازی طور پر مؤثر اور مضبوط ہونی چاہئیں، امریکہ اور برطانیہ میں یہی صورتحال ہے۔
سرد جنگ کے دوران میں کمیونسٹ رائٹرز یک جماعتی نظام کے دفاع میں اور اپنے نظام میں جمہوری قدروں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلیلیں دیتے رہے ہیں کہ ان کی جماعت میں جمہوریت ہے۔ اگرچہ مرکزیت ہے لیکن اسے بھی جمہوری بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح ’’جمہوری مرکزیت‘‘ (Democratic centralization) بہت معروف رہی ہے۔ کمیونزم کے علمبردار دوسری جماعت کی موجودگی کو اپنے نظام کے لیے نقصان دہ گردانتے تھے اور جمہوری مرکزیت اور ذاتی املاک کی عدم موجودگی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے خواہشمند تھے۔ سابقہ سوویت بلاک کی امریکہ کے خلاف محاذ آرائی، کمیونسٹ نظریے سے میچ کرتی تھی کیونکہ وہ اپنے نظام کے پھیلاؤ کے دوران میں اور پھیلاؤ کے بعد عالمی سطح پر کسی دوسری جماعت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر سرد جنگ کا فیصلہ کمیونسٹ ممالک کے حق میں ہوتا تو نتیجتاً پیدا ہونے والا یک قطبی نظام (Uni-polar system) ان کے نظریے کا عین ہوتا۔ لیکن سرد جنگ میں جیت امریکہ کی ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ اپنے جمہوری اصولوں کے مطابق عالمی سطح پر بھی ایک دوسری جماعت کو برداشت کرتا اور خیال کرتا کہ عالمی سطح پر جمہوری عمل جاری رہے، کیونکہ دو مؤثر جماعتیں عالمی سطح پر موجود ہیں لیکن امریکہ نے سابق سوویت یونین بلاک کے خلاف کام کرتے ہوئے ایک طرح سے غیر جمہوری عمل اختیار کیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران میں امریکہ جمہوریت اور آزادیوں کے پھیلاؤ کا پراپیگنڈا کرتا رہا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے ملک کے اندر جمہوریت کے قیام اور کامیابی کے لیے تو اپوزیشن کو ضروری خیال کرتا ہے لیکن یہی امریکہ جب اپنی جغرافیائی حدود سے باہر آتا ہے اور اپنے اسی نظام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جتن کرتا ہے تو اس کی اپروچ عملاً کمیونسٹ ہو جاتی ہے، وہی کمیونزم جس کے پھیلاؤ سے امریکہ اس لیے خوفزدہ تھا کہ وہ جمہوری قدروں کا حامل نہیں۔ (امریکہ کی طرف سے اب بھی چین پر تنقید ہوتی رہتی ہے) امریکی سیاسی فکر کے مطابق تو سابق سوویت یونین کا وجود بھی بطور اپوزیشن رہنا چاہیے تھا لیکن امریکیوں نے اسے ختم کر کے دم لیا۔
اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ اپنے ملک سے باہر امریکی اپروچ کمیونسٹ ڈھب پر ہے۔ وہ کسی بھی اپوزیشن کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں کیونکہ ان کا ’’نظام‘‘ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح کمیونسٹ ممالک اپنی جغرافیائی حدود میں معاشی وسائل کو ’’مرتکز‘‘ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے، عالمی سطح پر یہی طرز امریکہ نے اختیار کی ہے۔ امریکہ نے پوری دنیا کے معاشی وسائل صرف اپنے ہاں مرتکز کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ عالمی سطح پر ’’کمیونسٹ‘‘ بن کر ابھرا ہے۔ دنیا کو جو خوف کمیونسٹ ممالک سے تھا اور جس میں بہت زیادہ تخفیف سابقہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے ہوئی تھی، وہ اب امریکہ کی صورت میں پوری دنیا کا منہ چڑا رہا ہے۔
امریکہ نے کمیونسٹ پارٹی کی طرز پر ہی تو اپنی آمریت کو چھپانے کے لیے ایک طرح سے ’’جمہوری مرکزیت‘‘ کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے تاکہ جمہوریت پسندوں کو مطمئن کیا جا سکے۔ اقوامِ متحدہ اور دیگر عالمی داروں میں دنیا کی بے چارگی سے کون واقف نہیں؟ اسی طرح کمیونسٹ ممالک میں عوام اور پارٹی کارکنوں کی بے چارگی سے کون واقف نہیں تھا، اگرچہ ڈھنڈورا جمہوری مرکزیت کا پیٹا جاتا تھا۔ ایک جگہ اگر یک جماعتی نظام کی خامیاں تھیں تو دوسری جگہ یک قطبی نظام کا عفریت منہ کھولے کھڑا ہے۔ آج دنیا کو کسی ’’سپر گورباچوف‘‘ کی ضرورت ہے۔ ایک اور نکتہ قابل غور ہے، اگر امریکی رویہ اپنے ملک سے باہر اپنے نظریے کا معکوس ثابت ہوا ہے تو اس کا بھی امکان تھا کہ سابق سوویت یونین کا اپنے ملک سے باہر، عالمی سطح پر رویہ کمیونسٹ نظریے کا معکوس ہوتا اور دنیا یک قطبی نظام کا شکار نہ ہوتی، لیکن اس حوالے سے پورے تیقن سے بات کرنا بہرحال مشکل ہے۔
تاہم صورتحال میں آنے والی حالیہ تبدیلیوں کے نتیجے میں خود امریکہ کے اندر سے امریکی عوام کی آواز کی صورت میں ایک ’’سپر گورباچوف‘‘ کا ظہور شروع ہو گیا ہے۔ اب امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اپنی موجودہ روش کو برقرار رکھ سکے۔ امریکہ کو اپنے آمرانہ رجحانات کو Politicize کرنا ہو گا تاکہ یک قطبی نظام کا تاثر کم ہو سکے اور بظاہر اپوزیشن کی موجودگی کا احساس قائم ہو سکے۔ عالمی سطح پر امریکی آمریت کی سیاسی ہیئت (Politicization) امریکہ کے داخلی نظام میں تبدیلیوں کے بغیر ممکن نہیں ہو گی۔ امریکی تبدیلیوں کی نہج کا تعین کرنے میں درج ذیل امور کلیدی کردار ادا کریں گے:
- صدارتی الیکشن کے دوران میں بش اور الگور کے مابین جو کچھ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ امریکہ کی عالمی سطح پر سبکی ہوئی۔ امریکی صدارتی انتخابات کو براہ راست اور زیادہ شفاف کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کیونکہ جمہوریت کے حامی کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت میں کوئی نقص ظاہر ہو تو اس کا حل مزید جمہوریت ہے۔ مزید جمہوریت کے اس اصول کو امریکہ کے داخلی معاملات کی حد تک صدارتی الیکشن سے لے کر کسی بھی دستوری ادارے تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
- اس اصول کے اپنائے جانے کے بعد بھرپور پراپیگنڈا کیا جائے گا کہ دیکھیے ہم نے عوام کی آزادیوں کو وسعت بخشی ہے۔ اسی طرح صرف لفظوں کی حد تک اعادہ کیا جائے گا کہ ہم یہی آزادیاں پوری دنیا کے انسانوں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔
- زیادہ آزادیوں (More liberties) کے اسی نعرے کے تحت امریکی وفاق میں چند ایسی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں جن سے امریکہ کی وحدت اندرونی اعتبار سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو لیکن اس کی خارجی ہیئت یورپی یونین کی طرز پر استوار ہو۔
- حالیہ جنگ کے دوران میں اور جنگ کے بعد امریکہ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ نیا دور علاقائی اتحاد (Regional integration) کا دور ہے۔ یورپی یونین اس جنگ سے جو ثمرات سمیٹے گی وہ امریکہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو گا۔ اس علاقائی اتحاد کی چھتری تلے یورپی ممالک جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا آپشن رکھیں گے کیونکہ ان میں سے چند ممالک ان کی نمائندگی کرنے کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے جنگ میں موجود رہیں گے۔ امریکہ ’’دہشت گردی‘‘ کے نام پر تمام یورپ کو ہائی جیک نہیں کر سکے گا۔ اس طرح جنگ کے زیادہ منفی اثرات یورپ پر نہیں پڑ سکیں گے۔ اگر بالفرض جنگ کے اخراجات کی بابت بات چلے گی تو ہو سکتا ہے کہ یورپی یونین تقاضا کرے کہ اسے ایک ’’وحدت‘‘ کے طور پر ڈیل کیا جائے یعنی جو حصہ کسی ریاست کے حصے میں آتا ہے اتنا حصہ ہی سارا یورپ ادا کرے گا۔ بہرحال علاقائی اتحاد کا پلیٹ فارم یورپی ممالک کو بہتر سودے بازی کی پوزیشن میں رکھے گا۔
یورپی یونین کے نظام کی اسی نوع کی افادیت کے پیش نظر امریکہ کے لیے ناگزیر ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں کے تقاضوں کے مطابق اپنے نظام مین ہیئتی (Structural) تبدیلیاں کرے۔ یہ تبدیلیاں سیاسی اور دستوری نوعیت کی ہو سکتی ہیں۔ وفاق کو اس حد تک Decentralize یا مرکز گریز کیا جا سکتا ہے جیسے امریکی دستور کے ڈرافٹ کے مطابق تھا کیونکہ آغاز میں امریکی وفاق کا مرکز بہت مضبوط نہیں تھا۔ حالات کے تقاضوں اور امریکی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے مرکز بتدریج مضبوط ہوتا گیا۔ اسی طرح اب ایک معکوس عمل شروع ہو سکتا ہے۔ اس عمل میں مضمر خرابیوں کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کو زیادہ منظم اور مضبوط کیا جائے گا تاکہ دستور میں مرکز گریز رجحان کے باوجود سیاسی اعتبار سے امریکہ ایک وحدت رہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ یہ کام منظم سیاسی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں۔
ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مستقبل کی امریکی وحدت سیاسی و سماجی نوعیت کی ہو گی۔ اس سے یہ تاثر پھیلایا جائے گا کہ ہم نے اندرونی اختلافات کو جمہوری طریقے سے ایڈریس کیا ہے۔ اس سے لا محالہ عوام پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور امریکی قوم کی وحدت کا ایک نیا تفکیری عمل شروع ہو جائے گا جو طویل المیعاد اور پائیدار ہو گا۔ عالمی سطح پر امریکہ کو اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ کسی واقع کے حوالے سے USA کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکے کیونکہ پچاس ریاستوں کے مرکز گریز رجحان کے باعث ٹارگٹ کا تعین مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت یورپی یونین کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ اسے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یورپی کی سکیورٹی سیاسی اعتبار سے زیادہ پائیدار ہوئی ہے۔ یورپی یونین شاید یہ غلطی کبھی نہ کرے کہ Unity in diversity (تنوع میں وحدت) کو پھیلاتے ہوئے وفاق کی سطح پر لے جائے کیونکہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو گا۔
بات کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے اندر یعنی داخلی اعتبار سے چند بنیادی تبدیلیاں متوقع ہیں جس سے عالمی سطح پر اقوام کے مابین راہ و رسم کے نئے باب وا ہو سکتے ہیں اور امریکہ کے یک قطبی نظام کو طوالت بھی مل سکتی ہے۔
امریکی معاشرہ۔ سوچ میں تبدیلی کی جانب گامزن
ہَک گَٹمین
(مضمون نگار امریکہ کی ورمونٹ یونیورسٹی میں انگریزی کے استاذ ہیں۔ تحریر کا ترجمہ جناب نذیر حق نے کیا ہے۔)
گیارہ ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر دہشت گردی کے حملے، اس پر عالمی ردعمل، اور افغانستان پر (امریکی) بمباری کے بارے میں بہت سے تبصرے شائع ہو رہے ہیں۔ ان تبصروں میں سب سے زیادہ واضح اور تیز تبصرہ کسی کالم نگار نے نہیں کیا بلکہ ایک سیاسی شخصیت کیوبا کے صدر فیڈرل کاسترو نے کیا ہے۔ انہوں نے ۲۲ ستمبر کو (کیوبا کے دارالحکومت) ہوانا میں تقریر کرتے ہوئے جو ابتدائی جملے کہے ہیں وہ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کے برعکس، جو فیشنی انقلاب پسند ہیں، کاسترو نے واضح اور فیصلہ کن انداز میں دہشت گردی کے جواز سے انکار کیا ہے:
’’اس امر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج دہشت گردی ایک خطرناک اور اخلاقی طور پر ناقابلِ دفاع صورتحال ہے جس کا، اس کے منبع، اقتصادی اور سیاسی عناصر سے قطع نظر، جو اس کو روبہ عمل لانے کا موجب بنتے ہیں، مکمل انسداد کیا جانا بے حد ضروری ہے۔‘‘
مسٹر کاسترو نے دہشت گردوں کے حملہ کے امکانی نتائج کا بھی اندازہ لگایا ہے۔ ان کے الفاظ میں وزن ہے کیونکہ وہ سچے انقلابی ہیں:
’’اس دہشت گردی سے فائدہ کسے پہنچا ہے؟ انتہائی دائیں بازو والوں کو، نہایت پسماندہ فکر دائیں بازو کی قوتوں کو، ان لوگوں کو جو دنیا میں فروغ پذیر بغاوت کو کچلنا چاہتے ہیں، اور اس کرۂ ارض پر اگر کوئی ترقی پسند عنصر موجود ہے یا باقی بچ گیا ہے، اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، ایک بڑی نا انصافی تھی، یہ بہت بڑا جرم تھا جس کا ارتکاب، جس کی منصوبہ بندی اور جسے روبہ عمل لانے والے سبھی انسانیت کے مجرم ہیں۔‘‘
وہ شخص جو گزشتہ چالیس سال سے امریکی بالادستی کی مزاحمت کر رہا ہے، بخوبی جانتا بوجھتا ہے کہ ایک منصفانہ دنیا کا قیام ہی دراصل انسانی ترقی و تعمیر کا منصوبہ ہے۔ ایک زیادہ منصفانہ اور جمہوری دنیا کا قیام اور آزادی کی جدوجہد کا طویل کام ڈرامائی انداز میں ٹی وی پر ویڈیو ٹیپ چلا کر تو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ خوف و ہراس سے کوئی تعمیری کام تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو عدمِ استحکام ہی پیدا ہوتا ہے، اور عدمِ استحکام خلا پیدا کرتا ہے۔ جو اکثر و بیشتر فاشزم پر مبنی ایجنڈا رکھنے والی قوتوں کو ہی، خواہ یہ فاشزم مذہبی بنیاد پرست قوتیں روبہ کار لائیں یا کثیر القومی سرمایہ دار قوتوں کے جلو میں آئے، آگے آنے اور خلا کو پر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
مسٹر کاسترو کی بقیہ تقریر افغانستان میں امریکہ کی فوجی مداخلت کی مخالفت اور سرزنش پر مشتمل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر ترقی یافتہ غریب دنیا میں رہنے والے کروڑوں عوام اور قوموں کی معیشت پر ہی اس دہشت گردی کے نہایت خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے صدر جارج بش کی طرف سے بنیاد پرستانہ انداز میں نعرہ بازی پر بھی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ (یہ صدر بش کی طرف سے ’’صلیبی جنگ کے آغاز‘‘ کی باتوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے قوم سے خطاب کے دوران کی تھیں)۔ آخر مسٹر کاسترو امریکی ایمپائر کی غارت گر اور تند خوانا سے تو واقف ہیں نا!
صدر کاسترو کی طرف سے دہشت گردی کو مسترد کرنا، اور اس امر کی تفہیم کہ دہشت گرد انقلاب کی حمایت نہیں کرتے بلکہ رجعت پسندی کے فروغ کا سبب بنتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ ایسے مرد و خواتین کو پسند آئیں گے جو باہمی محبت اور مفاہمت چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس بنا پر ان کے خیالات کے مطابق امریکہ میں جو کچھ ہوا اس کے اثرات کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ امریکہ میں مقیم کسی بھی مبصر پر افغانستان میں امریکہ کی فوجی مداخلت کے علاوہ متعدد حقائق آشکارا ہوئے ہیں۔ یہ تسلیم کہ گیارہ ستمبر کے حادثات کے فوری اثرات خوف، عدمِ تحفظ اور فوجی جواب ہیں، لیکن جیسا کہ امریکہ کے عظیم ترین فلاسفر ریلف والڈو ایمرسن نے ۱۸۳۶ء میں لکھا تھا:
’’اگر کوئی ایسا زمانہ ہے جس میں پیدا ہونے کی کسی میں خواہش پیدا ہو تو کیا یہ انقلابات کا دور نہیں جب پرانے اور نئے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے، جب تمام افراد کے صبر کا امتحان خوف اور امید لے رہے ہوتے ہیں، جب پرانوں کی تاریخی شان و شوکت کی جگہ نئے دور کے شاندار امکانات کو دی جا سکتی ہو؟‘‘
ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بڑے ہی حیران کن نتائج پیدا ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ بش انتظامیہ کے بعض بنیادی مفروضے حالیہ دنوں کے دوران بالکل الٹ پڑ گئے ہیں۔ میں نے اس اخبار کے لیے تین ماہ قبل ایک مضمون سپردِ قلم کیا تھا جس میں، میں نے خارجہ امور میں امریکہ کی تنہائی پر سخت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ نے کیوٹو معاہدے کو مسترد کر دیا تھا جو کیمیائی اور حیاتیاتی جنگی تزویرات کی تحدید اور چھوٹے ہتھیاروں کی اسمگلنگ پر بین الاقوامی کنٹرول کے بارے میں تھا۔ دہشت گردوں کے حملے کے بعد صدر بش، نائب صدر ڈک چینی اور وزیر دفاع رمزفیلڈ نے، جو سبھی تنہائی پسندی کا شکار ہیں، اپنی ساری توجہ ’’بین الاقوامی کولیشن‘‘ قائم کرنے پر مرکوز کر دی۔ وہ اس خطرے کا تدارک کرنا چاہتے تھے کہ امریکہ اپنی فوجی قوت دوسروں سے صلاح مشورہ کیے بغیر استعمال کرے گا۔ وہ مسلمانوں کو بھی یہ یقین دلانے لگے کہ امریکہ تو مذہبی تنوع کو پسند کرتا ہے۔ اس ضمن میں اقوامِ متحدہ کو دیا جانے والا جواب خاص طور پر قابلِ غور ہے۔
چالیس سال سے زائد عرصے کے دوران میں ریپبلکن (پارٹی کے قائدین) اقوامِ متحدہ کو امریکہ کی خودمختاری پر تحدید قرار دیتے اور ادارے پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں۔ وہ اس بین الاقوامی ادارے کے فنڈز روکتے رہے اور اسے فنڈز کی کمی کا شکار بناتے رہے، حالانکہ امریکہ کے ذمے، جو دنیا کی امیر ترین ریاست ہے، یہ فنڈ بجا طور پر واجب الادا تھے۔ امریکی حکام اقوامِ متحدہ کی ہر اس کوشش کا مذاق اڑاتے رہے جو وہ دنیا بھر میں کسی بھی خطے میں عوام کو خطرات سے بچانے کے لیے کرتی رہی ہے۔ لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے دوران میں ریپبلکن صدر (جارج بش) نے اقوام متحدہ کو گویا گلے لگا رکھا ہے، وہ اسے ضروری قرار دے رہے ہیں تاکہ افغانستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں قرارداد منظور کرا سکیں۔ اور وہ دنیا بھر کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کی تصدیق و توثیق کرتے پھرتے ہیں۔
۔۔۔۔ لیکن اب بھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی یک طرفہ کے بجائے اجتماعیت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے شمالی امریکہ اور یورپ کی سرحدوں سے آگے کسی اور دنیا کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے مگر اب وہ اس احساس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ترقی پذیر دنیا ایک غیر معمولی پیچیدہ دنیا ہے۔ مگر امریکہ کی برسراقتدار قوتیں ابھی پوری طرح اس بات پر تیار نہیں کہ موجودہ عالمی نظام پر نظرثانی ہونی چاہیے جس میں دولت مند قومیں عالمی معیشت پر چھائی ہوئی ہیں اور یہ بات دنیا بھر کے شہریوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ اس امر کا کوئی امکان بھی نہیں کہ واشنگٹن کی سیاست یا معیشت کاری دنیا میں دولت یا آمدنی کی غیر مساوی تقسیم کو تبدیل کرنے میں کوئی کردار ادا کرے گی، لیکن دولت کی منصفانہ تقسیم کے بغیر ترقی پذیر دنیا اپنے معاشرتی (ترقی کے) اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ دولت کی تقسیم میں اہم اور واضح تبدیلی کے بغیر اربوں انسان غربت کی بھٹی میں جلتے رہیں گے، بیماریوں کے تنور میں جھلستے رہیں گے اور ان کی توقعات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ دہشت گردی کے اسباب خواہ کچھ بھی ہوں، اس کی نرسری تو مایوسی اور غصہ ہی ہیں، جو ایک ایسی دنیا میں مقیم انسانوں میں جنم لیتے ہیں جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں لیکن وہاں دولت وافر مقدار میں موجود ہو البتہ اس کی منصفانہ تقسیم ناپید ہو۔
دہشت گردی کا ایک اور نتیجہ امریکی عوام کی آگاہی میں تبدیلی بھی ہے۔ اگرچہ امریکی عوام بھی دنیا کے دوسرے عوام سے مختلف نہیں ہیں، جن کی ایک خاصی بڑی تعداد یا تو اس نوع کی خبروں کو نظرانداز کر دیتی ہے یا پھر اپنے سابقہ نظریات میں تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن اب امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ۱۰ ستمبر کی نسبت آج دنیا کی صورتحال کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اکیسویں صدی میں زندگی زیادہ غیر محفوظ اور خطرات سے پُر ہو سکتی ہے۔ اس وقت بہت سے امریکیوں کے دل میں تین انواع کی بصیرت نے جنم لیا ہے:
- دنیا امریکہ کی سرحدوں کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی۔
- امریکی شہریوں کی ایک بڑی تعداد میں یہ احساس اور ادراک بھی پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں بہت سی اقوام اور معاشرے ہیں جو آزاد ہیں، خودمختار ہیں، اور وہ امریکی امداد، ثقافت اور اثرورسوخ کے بغیر بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران میں امریکیوں کو کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اقوام کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے اور اقوام کے درمیان تعلقات بھی اسی طرح پیچیدہ اور تہ در تہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج ان میں ان باتوں کا ادراک اور احساس پوری طرح بیدار ہو چکا ہے۔ صرف وہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو امریکہ میں سالوں سے رہ رہے ہیں، یا وہ جو امریکہ یاترا پر اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ بے حد حیران کن امر ہے کہ امریکی فوج کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ملک پر چڑھ دوڑیں بلکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ فوجی کارروائی سے قبل اس کے بین الاقوامی نتائج کو بھی مدنظر رکھا جا رہا ہے۔ امریکیوں کے بارے میں یہ تصور کہ وہ چرواہے ہیں، جیسا کہ پرانی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، یا پھر وہ پولیس والے ہیں جیسا کہ کئی فلموں میں انہیں پیش کیا جا رہا ہے جو اپنا پستول نکال کر ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور ہر سامنے آنے والے مخالف کو گولی کا نشانہ بناتے چلے جاتے ہیں، اب مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ افغانستان پر فضائی بمباری کے جواز یا انصاف کے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچے، لیکن یہ (اقدام) سوچا سمجھا ہے اور کسی ناراض گن مین کا فوری ردعمل نہیں کہ وہ ہر اس چیز کو گولی کا نشانہ بناتا چلا جائے جو اسے حرکت کرتی ہوئی نظر آئے۔
- مغربی دنیا میں عموماً اور امریکہ میں خصوصاً یہ آگاہی بڑھ رہی ہے کہ دنیا کی آبادی کے تیسرے حصے سے زیادہ افراد قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ دو ماہ قبل غالباً ۵ فیصد کے قریب امریکی یہ جانتے تھے کہ اسلام دنیا میں کتنی دور دور تک پھیل چکا ہے۔ مگر آج امریکیوں کی اکثریت اسلام کی وسعت کے بارے میں آگاہ ہو چکی ہے۔ اب بہت سے امریکی ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عیسائیت کی طرح اسلام میں بھی کئی مکاتبِ فکر ہیں، کئی فرقے ہیں اور ان سب کی اندرونی روایات بھی ہیں۔ نیویارک میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد کے دنوں میں اگرچہ امریکہ کے گلی بازاروں میں مسلمانوں پر حملوں، ان سے گالی گلوچ کرنے اور تنگ کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ پہلے سے بہت زیادہ حد تک صبر و تحمل، برداشت، باہمی تصورات اور عقائد کے اختلاف کو قبول کرنے، خصوصاً اسلام کی مذہبی رسوم پر عمل اور اسلامی اقدار سے تعرض نہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اگر امریکہ کا کوئی مخصوص دعوٰی ہے جس پر امریکی عوام بھی فخر کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ امریکی شہری اختلافات کو برداشت کرنے اور معاشرتی گوناگونی کو قبول کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ اس امر کی تردید ناممکن ہے کہ امریکی معاشرہ اپنی امنگوں اور خواہشات کے مطابق عمل پیرا رہتا ہے، لیکن بسا اوقات، خصوصاً گزشتہ ہفتوں کے دوران میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی معاشرہ زیادہ تحمل و برداشت اور نوعِ انسانی کی گوناگونی کی تفہیم کا ثبوت دے رہا ہے۔
امریکی معاشرے کے ضمیر میں تبدیلی شاید سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ پورے امریکہ میں مرد اور خواتین یہ سوال پوچھتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ کیسے ہوا؟ کیونکر ہوا؟ ایک سطح پر تو، جیسا کہ صدر فیڈرل کاسترو نے بھی ذکر کیا ہے، اس سوال کا جواب یہی ہے کہ کسی بھی اخلاقی نظم یا انقلابی حکمتِ عملی میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک اور سطح پر، امریکی معاشرے میں اس امر کا احساس بھی بڑھ رہا ہے کہ دنیا کے بہت سے انسانوں اور لاتعداد معاشروں کو امریکی قوم سے بالکل صحیح شکایات اور گلے شکوے ہیں۔ آج امریکہ کے شہری انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں، جو قبل ازیں کبھی محسوس نہیں کی گئی، کہ ان کی قوم کا عالمی نظم یا دنیا کے ڈھانچے میں نہایت بنیادی کردار ہے جو معاشروں کو غریب اور پس ماندہ معاشروں سے جدا کرتا ہے، اور امریکہ ایک بین الاقوامی پولیس مین ہونے کی حیثیت میں امیر اور غریب معاشروں کے درمیان اس فرق کو قائم رکھتا ہے۔
میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اقتصادی انصاف کے لیے جدوجہد میں گزارا ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ ان دنوں امریکہ میں ہر طرف امریکیوں کی ان پالیسیوں کی مذمت ہو رہی ہے جن کے باعث اس کرۂ ارض پر آباد نصف سے زائد انسانوں پر مسلسل ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ اس مذمت میں امریکی نوجوان، بوڑھے، پڑھے لکھے اور مراعات یافتہ طبقہ کے لوگ اور عام مزدور، عام شہری تک بیک زبان شامل ہیں۔ امریکہ میں جہاں بھی چار افراد مل بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کھیلوں، فلموں یا موسم پر نہیں ہوتی بلکہ وہ امریکہ کی سیاسی پالیسیوں پر بحث کرتے نظر آتے ہیں حالانکہ قبل ازیں ایسا نہیں تھا۔ یہ بات چیت واقعی بعض مرکزی اور بنیادی مسائل پر ہی ہوتی ہے۔ مثلاً امریکہ نے دنیا میں غربت کو قائم رکھنے کے لیے کتنا زیادہ کردار ادا کیا ہے؟ لوگ اس بات پر امریکہ کا محاسبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ دنیا میں جمہوری اور منتخب حکومتوں کے بجائے اپنی پسند کے چند افراد پر مشتمل حکومتوں کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور امریکہ مختلف خطوں اور ممالک میں عدمِ استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ باتیں امریکی عوام کو مسلسل پریشان رکھ رہی ہیں۔
امریکیوں کی بڑی تعداد ان باتوں کے بارے میں اظہار خیال کرتی نظر آتی ہے اور وہ امریکہ کی ان خامیوں کو خوب سمجھ رہے ہیں۔ مگر بش انتظامیہ کے بڑے، فوجی جرنیل اور مالیاتی اداروں میں بیٹھے ہوئے جغادریوں کو ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جب تک برسراقتدار قوتیں، ان میں سیاسی اور معاشی دونوں شامل ہیں، ان باتوں کا ادراک نہیں کریں گی اور امریکی شہریوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے خدشات اور خطرات کا احساس نہیں کریں گی، ترقی پذیر دنیا اور امریکہ کے درمیان بنیادی اقتصادی تعلقات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو گی۔ لیکن اس امر کی امید کی جا سکتی ہے کہ سوچ میں تبدیلی ضرور آ رہی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ شاعر شیلے نے لکھا تھا ’’اگر موسمِ سرما آتا ہے تو کیا موسمِ بہار بہت دور ہو سکتا ہے؟‘‘ اگرچہ ان سب باتوں کا مثبت جواب یقینی ہرگز نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ’’اگر عوام بدل جائیں تو کیا ان کی حکومت ان سے دور پیچھے رہ سکتی ہے؟‘‘
(بشکریہ روزنامہ پاکستان)
ورلڈ ٹریڈ سنٹر کا المیہ ۔۔ اصل گیم
عبد الرشید ارشد
ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے المیے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے بلکہ اس سے پیدا شدہ صورتحال پربھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اس المیے کی تہہ میں چھپے طوفان پر شایدبہت ہی کم لوگوں کی نگاہ ہو گی۔ ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی تباہی کوئی جذباتی کارروائی نہیں ہے بلکہ یہ لمبی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ اس منصوبہ بندی کی کڑیاں بہت دور تک جاتی ہیں۔ وثائقِ یہودیت (Protocols) پر گہری نظر رکھنے والوں کے لیے اس قضیے کو، اس کی تہہ میں چھپے طوفانوں کو سمجھنا سہل ہے۔
یہود کے منصوبہ میں سرفہرست عالمی سطح پر اقتدارِ اعلٰی کی منزل ہے جس کا پایۂ تخت ’القدس‘ ہو گا جو عظیم تر اسرائیل کا بھی پایۂ تخت ہو گا۔عظیم اسرائیل کا حصول ان کا خفیہ منصوبہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ’القدس‘ کے ساتھ اسرائیلی مملکت کا قیام تھا جس میں وہ ۱۹۴۸ء میں برطانیہ کی سرپرستی سے کامیاب ہو گئے۔ نصف صدی کے بعد اب انہوں نے دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیا ہے۔ عظیم اسرائیل میں ارضِ فلسطین کے علاوہ ترکی، شام، عراق، اردن، کویت، بحرین، عرب امارات، سعودیہ کا بیشتر حصہ بشمول مدینہ منورہ، سوڈان، مصر وغیرہ شامل کرنے کی آرزو اور عملی کوشش ہے۔
اس آرزو کی تکمیل اکیلے اسرائیل کے بس میں نہیں ہے لہٰذا اس نے مداری کا رول امریکہ اور برطانیہ کے سپرد کر دیا ہے اور امریکہ و یورپ پر اپنے سونے کے زور پر حاوی ہونے کے بعد اور انہیں یہ یقین دلا کر کہ ہمارا تمہارا دشمن نمبر ایک اسلام اور مسلمان ہیں، اپنا ہم نوا بنا لیا ہے۔ یہودی مسلمان ممالک کو کمزور کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے خود پسِ پردہ رہ کر وقتاً فوقتاً اپنی منصوبہ بندی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے خود یہود کی زبانی:
’’وہ کون ہے اور کیا ہے جو نادیدہ قوت پر قابض ہو سکتا ہے؟ بالیقین یہی ہماری قوت ہے۔ صہیونیت کے کارندے ہمارے لیے پردے کا کام دیتے ہیں جس کے پیچھے رہ کر ہم مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ منصوبۂ عمل ہمارا تیار کردہ ہوتا ہے مگر اس کے اسرار و رموز ہمیشہ عوام کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں‘‘۔ (پروٹوکولز ۴ : ۲)
منصوبۂ عمل ایران عراق جنگ کا ہو، عراق کویت کا ہو، عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی یلغار کا ہو، یا افغانستان پر امریکی دہشت گردی کا ہو، اس کے حقیقی منصوبہ ساز مذکورہ اقتباس کی روشنی میں یہود ہیں، اور ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملوں کی منصوبہ بندی کے خالق بھی وہی ہیں۔ مذکورہ اور موجودہ جنگوں کے منصوبہ کو ذیل کے اقتباس میں ملاحظہ فرمائیے:
’’جہاں تک ممکن ہو ہمیں غیر یہود کو ایسی جنگوں میں الجھانا ہے جس سے انہیں کسی علاقے پر قبضہ نصیب نہ ہو بلکہ جو جنگ کے نتیجے میں تباہی سے دوچار ہو کر بدحال ہوں‘‘۔ (پروٹوکولز ۲ : ۱)
اس مختصر اقتباس میں ایران عراق جنگ، روس چیچنیا جنگ، عراق کویت جنگ، اور اب آخر میں امریکہ اور افغانستان جنگ کا جائزہ لے کر یہود کی منصوبہ بندی کی صداقت کو پرکھ لیجئے۔ بات سمجھنے میں کچھ بھی تو مشکل نہیں ہے۔ اسرائیل کو مذہبی ایران اور مضبوط ایٹمی قوت کے قریب عراق سے خطرہ تھا۔ ایٹمی پلانٹ خود تباہ کر دیا اور پھر ایران عراق کے سینگ پھنسا دیے کہ ان کا اسلحہ، ان کے وسائل، ان کی افرادی قوت جو اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، بھسم ہو جائے، اور عرب عجم کا تعصب ہوا پکڑے۔ اسرائیل اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہوا اور مسلمان کی بصیرت بازی ہار گئی جس پر مذکورہ ہر محاذ گواہی دے رہا ہے۔
جب طویل جنگ کے باوجود عربوں کی مالی مدد کے سبب عراق کو مضبوط دیکھا تو اسے کمزور بلکہ برباد کرنے اور عظیم اسرائیل کے منصوبے کو ایک قدم آگے بڑھانے کی خاطر پہلے عراق کو کویت پر حملے کے لیے اکسایا، اور پھر کویت کے ساتھ سعودی عرب پر بھی عراقی دہشت کے سائے دکھا کر سعودی عرب کی سرزمین پر باقاعدہ چھاؤنی بنا کر مستقل ڈیرے ڈال دیے۔ کویت اور سعودیہ کے ’’محسن‘‘ نے عربوں سے اپنا برسوں کا بجٹ وصول کیا، پرانا اسلحہ منہ مانگے داموں عراق پر گرایا، نیا اسلحہ عربوں کے خرچ پر انہی کی سرزمین پر ٹیسٹ کر لیا، اور جنگ کے نام پر ہنگامے میں عربوں کے خرچ پر جدید اسلحہ اسرائیل پہنچایا، عربوں کے سیال سونے پر قبضہ جمانے کے ساتھ عظیم اسرائیل کی تکمیل کے لیے مدینہ سے قریب تر پہنچ گئے۔
عظیم اسرائیل کے خواب کو شرمندۂ تعبیر ہوتے دیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام اور اس کی فوج ہے کہ یہ عربوں سے بڑھ کر ان کے خیرخواہ ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو کمزور کرنا اس کو بے بس بنانا اسرائیل کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ کام بھارت سے ہو سکتا ہے یا امریکہ کے ذریعے سے، مگر انتہائی قرینے سے۔ پاکستان دشمنی دیکھئے:
’’عالمی یہودی تحریک کو اپنے لیے پاکستان کے خطرے کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان اس کا پہلا ہدف ہونا چاہیے کیونکہ یہ نظریاتی ریاست یہودیوں کی بقا کے لیے سخت خطرہ ہے اور یہ کہ سارا پاکستان عربوں سے محبت اور یہودیوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس طرح عربوں سے ان کی محبت ہمارے لیے عربوں کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا عالمی یہودی تنظیم کو پاکستان کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ بھارت پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس کی ہندو آبادی مسلمانوں کی ازلی دشمن ہے جس پر تاریخ گواہ ہے۔ بھارت کے ہندو کی اس مسلم دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں بھارت کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دشمنی کی خلیج کو وسیع سے وسیع تر کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہودیوں کے یہ دشمن ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں۔‘‘ (اسرائیل وزیراعظم بن گویان کی تقریر، بحوالہ جیوش کرانیکل، ۹ اگست ۱۹۶۷ء)
’’پاکستان کی فوج اپنے پیغمبر کے لیے بے پناہ محبت رکھتی ہے اور یہی وہ رشتہ ہے جو عربوں کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی محبت، وسعت طلب عالمی صہیونیت اور مضبوط اسرائیل کے لیے شدید خطرہ ہے، لہٰذا یہودیوں کے لیے یہ انتہائی اہم مشن ہے کہ ہر صورت اور ہر حال میں پاکستانی فوج کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی محبت کو کھرچ دے۔‘‘ (امریکی ملٹری ایکسپرٹ پروفیسر ہرنز کی رپورٹ)
سعودیہ اور کویت میں قدم جما لینے کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بے بس کرنا ضروری تھا اور یہ بے بسی مکمل صرف اس صورت میں ممکن تھی کہ اس کے شمال میں اسلامی ریاست افغانستان کو بے بس کر دیا جائے اور وہاں لا دینی حکومت قائم ہو جو امریکہ اور بھارت یا بالفاظ دیگر یہود کے اشارۂ ابرو پر کام کرے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان سینڈوچ بنا رہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مشکل لمحات کے دوست چین کو پاکستان سے بدظن کر کے پیچھے ہٹا کر پاکستان کو تنہا کر دیا جائے۔
یہ بہت بڑا کام تھا اور اس کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بڑا کام کیا جائے جس سے امریکہ کی دہشت اور وحشت کو مسلمان حکمرانوں کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر جو امریکی وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا اور پینٹاگون پر جو امریکی عظمت اور عالمی غنڈہ گردی کی علامت ہے، کاری ضرب لگا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا رخ پاکستان اور افغانستان کی طرف پھیرنا ضروری سمجھا گیا۔
’’ہماری شناخت ’قوت‘ اور ’اعتماد بناؤ‘ میں ہے۔ سیاسی فتح کا راز قوت میں مضمر ہے بشرطیکہ اسے سیاستدانوں کی بنیادی مطلوبہ ضرورت اور صلاحیت کے پردے میں چھپا کر استعمال کیا گیا ہو۔ تشدد راہنما اصول ہونا چاہیے۔ اور ان حکمرانوں کے لیے، جو حکمرانی کو کسی نئی قوت کے گماشتوں کے ہاتھ میں نہ دینا چاہتے ہوں، ان کے لیے یہ مکر میں لپٹا ہوا ’اعتماد بناؤ‘ اصول ہے۔ یہ برائی ہی ہمیں ’’مطلوبہ خیر‘‘ تک لے جانے کا آخری ذریعہ ہے۔‘‘ (پروٹوکولز ۱ : ۲۳)
ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے المناک تشدد کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر ایک بار پھر مذکورہ اقتباس پڑھیے بلکہ ان الفاظ پر ذرا رکیے کہ ’’یہ برائی ہمیں مطلوبہ خیر تک لے جانے کا آخری ذریعہ ہے‘‘ اور سوچیے کہ ٹریڈ سنٹر کی تباہی والی برائی عظیم تر اسرائیل کی منزل تک لے جانے کا آخری ذریعہ ہے، اس ذریعہ تک رسائی کے لیے ان کا مؤثر ہتھیار میڈیا ہے۔
اب آئیے اقتباس میں ’’قوت اور اعتماد بناؤ‘‘ پر توجہ دیں۔ امریکہ میں یہود کی قوت اور یہود پر اعتماد کس کی نظر سے اوجھل ہے؟ امریکہ کے آج تک ۱۷ صدور یہودی خفیہ تنظیم فری میسنز کے باضابطہ رکن رہے۔ آج صدارتی الیکشن یہود کی مدد کے بغیر جیتنا ناممکن ہے۔ کوئی بش کی طرح جیت لے تو صدر رہنا مشکل۔ بش جن حالات سے دوچار رہے وہ ہر کسی کے سامنے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سنٹر اور پینٹاگون کے لیے اس المیے سے ’’خیر‘‘ نکالنے کا کام میڈیا کے ذمے تھا جو اس نے بڑی خوبی سے نبھایا کہ امریکی حکومت کی طرح مغربی میڈیا بھی یہود کا زرخرید غلام ہے۔ ادھر اغوا شدہ جہاد ’’قوت اور اعتماد بناؤ‘‘ کے فارمولے پر عمل کرتے، امریکی ایجنسیوں کی کارکردگی کا مذاق اڑاتے، پینٹاگون اور ٹریڈ سنٹر ٹاور سے ٹکرائے، ادھر میڈیا نے اس کا رشتہ اسامہ بن لادن اور طالبان سے جوڑنا شروع کر دیا۔ یوں گوبلز کی اولاد غصے میں پاگل بش اور اس کی حکومت کو اتنا آگے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی کہ بش آخری صلیبی جنگ لڑنے نکل کھڑے ہوئے۔
میڈیا کے ضمن میں یہود کا نقطۂ نظر ملاحظہ فرمائیے:
’’چند مستثنیات کو چھوڑ کر پہلے ہی عالمی سطح پر پریس ہمارے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے۔‘‘ (پروٹوکولز ۷ : ۵)
’’پریس کا کردار یہ ہے کہ وہ ہماری ناگزیر ترجیحات کو مؤثر انداز میں پھیلائے، عوامی شکایات کو اجاگر کر کے عوام میں بے چینی پھیلائے۔‘‘ (پروٹوکولز ۲ : ۵)
ان اقتباسات کی روشنی میں آپ ۱۱ ستمبر اور اس کے بعد آج تک امریکہ کے اندر اور باہر پریس کا کردار دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ میڈیا کس طرح یہود کی ’’ناگزیر ترجیحات‘‘ کی تکمیل کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ معمولی غوروفکر سے یہ اندازہ کرنا بھی کچھ مشکل نہیں کہ پاکستانی میڈیا بھی یہود کے عالمی میڈیا کی سُر سے سُر ملا کر حقِ نمک ادا کر رہا ہے۔
مذکورہ تفصیل سے جو بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ عظیم تر اسرائیل کے خواب کو شرمندۂ تعبیر کرنے کے لیے یہود کی منصوبہ بندی ایک تدریج کے ساتھ بڑے مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلے روس کے سپر پاور ہونے کے خناس کو افغانستان میں پھنسا کر رسوا کیا۔ اب دنیا میں امریکہ سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے۔ اسے بڑے سلیقے سے افغانستان میں لا کر عسکری اور معاشرتی میدان میں بانجھ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اندرونی طور پر اسے کمزور کر کے عالمی اقتدار کے راستے کا یہ روڑا ہٹا دیا جائے۔ برطانیہ ہو یا فرانس اور یورپ کے دیگر ممالک پہلے ہی یہود کے باج گزار ہیں۔
امریکہ، روس اور دیگر یورپی ممالک کے بعد لے دے کے اسلام یہود کے مدِ مقابل رہ جاتا ہے۔ اسلامی بلاک کو امریکہ اور یورپی بلاک کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا جائے تو یہود کے لیے میدان خالی ہو گا۔ اسلامی بلاک میں صرف پاکستان ہے جو ایٹمی قوت بھی ہے لہٰذا اس کو دوست بن کر ڈالروں کا زہر پلا کر ختم کیا جائے۔ دوستی کی انتہا یہ کہ روزنامہ خبریں ۱۷ اکتوبر کے مطابق اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے کرتا دھرتا امریکی مہمانوں کو اپنے ایٹمی مقامات تک لے گئے۔ بقول اخبار انہیں ایٹمی اسلحہ کا اسٹور بھی دکھایا جس پر وفد نے اسٹوریج کے لیے تجاویز دینے کا وعدہ کیا کہ موجودہ سکیورٹی نظام ان کے نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے۔
خالق اپنی مخلوق کی خوبیوں اور خامیوں سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی مخلوق کو حکم دے، نصیحت کرے کہ فلاں سے دوستی کرو اور فلاں سے بچتے رہو، فلاں دوست ہے اور فلاں دشمن ہے تو حقیقی نصیحت یہی ہے۔ مسلمان کے خالق نے اپنی کتاب میں بار بار تاکید فرمائی کہ یہود و نصارٰی کو دوست نہ بناؤ۔ مگر ہم ہیں کہ بش کو عقلِ کل سمجھ کر اس کی دوستی پر نازاں ہیں اور اس بے یقین کی بات پر یقین کر کے اپنی فضا، اپنے اڈے اس کے سپرد کر دیے جو دس روز کا کہہ کر خیمے میں اونٹ کی طرح داخل ہوا اور اب دس سالہ قیام کی نویدِ مسرت سنا رہا ہے۔
افغان مجاہدین اور اسامہ بن لادن نے گزرے کل افغانستان (میں روس) کے خلاف پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی تھی کہ بھارت کا یار اور (امریکی U2 جاسوس پروازوں کے سبب) پاکستان کا دشمن روس افغانستان کے راستے بلوچستان کو تاراج کر کے خلیج کے گرم پانیوں پر ڈیرا ڈالنے پر مصر تھا تاکہ روس بھارت کے درمیان پاکستان کا وجود ہر لمحہ خطرہ میں رہے، پاکستان لمحہ بہ لمحہ روس اور بھارت سے آزادی کی بھیک مانگتا پھرے۔ ہماری بدنصیبی کہ ہم نے افغان مجاہدین اور اسامہ بن لادن کی قربانیوں کو فراموش ہی نہیں کیا، نمک حرامی پر بھی اتر آئے۔ گزرے کل کی طرح آج پھر وہی افغانستان اور وہی اسامہ بن لادن کفر کے دوسرے روپ عالمی دہشت گرد کے خلاف بے یارومددگار، بے ساز و سامان، محض اپنے رب کی رحمت کے سہارے سینہ سپر ہیں۔ جس دہشت گرد کی ایک ٹیلی فون کال پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تین جنگیں لڑنے کے دعوے دار فوجی صدر کا پتہ پانی ہو گیا، اس کے مقابل اللہ کے سپاہی ملا محمد عمر مجاہد اور اسامہ بن لادن ڈٹ گئے۔ فرق صرف ایک سجدہ کا ہے جو شاید صدر مشرف بھی کرتے ہوں گے اور ملا محمد عمر، طالبان اور اسامہ بن کرتے ہیں۔ اور یہ سجدہ
؎ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
کاش ملا محمد عمر، اسامہ بن لادن اور طالبان کی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قیادت نے بھی ویسا ہی ایک سجدہ کر لیا ہوتا اور مسلّمہ عالمی دہشت گرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے کہ مسلمان جسدِ واحد ہیں، افغانستان کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی اور ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ میدانِ حرب میں آمنے سامنے تھے کہ حضرت امیر معاویہؓ کو کافر دشمن نے حضرت علیؓ کے مقابلے میں مدد اور تعاون کی پیشکش کی۔ حضرت امیر معاویہؓ کا جواب تھا کہ ہمارا معاملہ دو بھائیوں کا ہے، اگر تم نے ایسی جرأت کی تو علیؓ کی طرف سے تمہارے خلاف لڑنے والا پہلا شخص معاویہؓ ہو گا۔ آج یہ بات مشرف صاحب کے کہنے کی تھی، شمالی اتحاد کے کہنے کی تھی، ایران و عرب کے کہنے کی تھی، مگر
بت صنم خانے میں کہتے ہیں مسلمان گئے
ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے
منزلِ دہر سے اونٹوں کے حدی خوان گئے
اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے
افغانستان کو برباد کر کے اپنی پسند کی حکومت بنوانے والے اور ان کے دوسرے ہم نوا حکمران بصیرت سے عاری یہ بھول گئے کہ یہود و نصارٰی کا ٹارگٹ اسلام اور مسلمان ہیں۔ یہود و نصارٰی مسلم حکمرانوں سے زیادہ چالاک، عیار و مکار اور عقل مند ہیں۔ جسے آج وہ عالمی دہشت گرد کہہ کر ان سے معاونت لے رہے ہیں وہ اسلام کا فلسفۂ جہاد ہے جسے مٹانے کا عزم لے کر بش امریکہ سے نکلا ہے۔ بش کا ٹارگٹ اسامہ یا ملا محمد عمر نہیں ہے، اس کا ہدف اسلام، مسلمان اور مسلمان کا جہاد ہے جس پر کاری ضرب لگا کر وہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ اور کس قدر بدنصیبی کی بات ہے اس نیک مقصد میں مسلمان کہلوانے والے حکمران اس کے معاون و مددگار ہیں۔
بہ مشیتِ اللہ تعالٰی افغان مجاہدین اور اسامہ بن لادن سرخرو ہوں گے۔ فتح و نصرت ان کا مقدر ہو گی کہ ان کی سپر پاور جبار و قہار و عزیز بھی ہے سریع الحساب بھی، اور ان کے ہتھیار کلمہ طیبہ کے مقابلے میں آج تک کسی فیکٹری میں بہتر ہتھیار نہیں بنا۔ دنیا میں ان کا انعام سکینت ہے جو کسی مسلمان حکمران کا مقدر نہیں اور محشر میں دیدارِ باری تعالٰی انہیں نصیب ہو گا۔ دنیا میں کفر کے ساتھی محشر میں ان کے ساتھی ہوں گے اگر توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔
امتِ محمدیہ کا امتیاز
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ
امتِ اسلامیہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے اور یہ پیغام اس کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات پر حاوی ہے۔ اس کا منصب قیادت و رہنمائی اور دنیا کی نگرانی و احتساب کا منصب ہے۔ قرآن مجید نے بہت قوت اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے:
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنھون عن المنکر وتومنون باللہ۔ (آل عمران ۱۱۰)
’’(اے پیروانِ دعوتِ ایمان) تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں (کی رہنمائی و اصلاح) کے لیے ظہور میں آئی ہے، تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو‘‘۔
دوسری جگہ کہا گیا ہے:
وکذالک جعلناکم امۃ وسطًا لتکونوا شھدآء علی الناس۔ (البقرہ ۱۴۳)
’’اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو‘‘۔
اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس امت کی جگہ قافلہ کے پیچھے اور شاگردوں اور حاشیہ برداروں کی صف میں ہو، اور وہ دوسری اقوام کے سہارے زندہ رہے۔ اور قیادت و رہنمائی، امر و نہی اور ذہنی و فکری آزادی کے بجائے تقلید اور نقل، اطاعت و سپراندازی پر راضی اور مطمئن ہو۔ اس کے صحیح موقف کی مثال اس شریف، قوی الارادہ اور آزاد ضمیر شخص سے دی جا سکتی ہے جو ضرورت و احتیاج کے وقت دوسروں سے اپنے ارادہ و اختیار سے وہ چیزیں قبول کرتا ہے جو اس کے حالات کے مطابق ہوں اور اس کی شخصیت اور خود اعتمادی کو مجروح نہ کرتی ہوں، اور ان چیزوں کو مسترد کر دیتا ہے جو اس کی شخصیت اور حیثیت کے مطابق نہ ہوں یا اس کو کمزور کرتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کو کسی دوسری قوم کے شعائر اور امتیازات اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
(مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی کشمکش)
شہید کا درجہ
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
نبوت اور رسالت کے بعد شہادت کا رتبہ ایک بہت اونچا رتبہ ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کے انقطاع کے باوجود شہیدوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عمدہ اور باعزت زندگی حاصل ہوتی ہے اور ان کی شان کے لائق ان کو پروردگار کے ہاں سے رزق نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربھم یرزقون۔ (آل عمران ۱۶۹)
’’اور تم ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے‘‘۔
ساری مخلوق میں جو رتبہ، درجہ اور شان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور خصوصیت سے ختمِ نبوت کا جو بلند مقام آپ کو مرحمت ہوا ہے وہ صرف آپ سے مختص ہے۔ بایں ہمہ آپ نے مقامِ شہادت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک موقع پر فرمایا کہ
’’میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں‘‘۔ (بخاری)
جس امر کے حاصل کرنے کے لیے آپ بار بار آرزو کریں، اس کے بہتر اور افضل ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟
حضرت مقدام بن معدی کربؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
’’شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں چھ خصوصیتیں ہیں:
- عین شہادت کے موقع پر اس کو مغفرت کی سند حاصل ہو جاتی ہے۔
- قبر کے عذاب سے اس کو پناہ مل جاتی ہے۔
- قیامت کے دن سخت گھبراہٹ کے موقع پر اس کو امن نصیب ہوگا۔
- اس کے سر پر وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج کے ایک موتی کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کے خزانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
- اس کو بَہتر حوریں عنایت ہوں گی۔
- اور اس کو اپنی برادری کے ستر آدمیوں کی شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا۔‘‘
(ترمذی و قال صحیح)