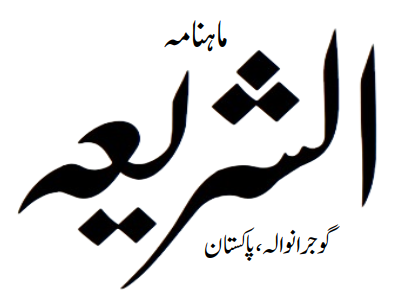جنوری ۱۹۹۰ء
جہادِ افغانستان کے خلاف امریکی سازش
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
امریکی سینیٹر مسٹر سٹیفن سولارز ان دنوں پاکستان آئے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ افغانستان کے مسئلہ پر ایک فارمولا لائے ہیں جس کا بنیادی نکتہ افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ کو افغانستان میں کوئی کردار سونپنا بیان کیا جاتا ہے۔ سٹیفن سولارز وہی صاحب ہیں جو امریکہ کی رائے عامہ کو پاکستان اور اسلامی قوتوں کے خلاف منظم کرنے کی مہم کے سرخیل بنے ہوئے ہیں۔ انہیں پاکستان میں بالخصوص اسلامی قوتوں کے آگے آنے اور اسلامی قوانین کے نفاذ و غلبہ سے چڑ ہے اور وہ افغانستان میں مجاہدین کی حکومت کو ہر قیمت پر روکنے کی سازش کا ایک اہم کردار ہیں۔
افغانستان میں اس وقت امریکہ اور روس میں اس بات پر کشمکش جاری ہے کہ روس اپنے نجیب اللہ کو کابل کے اقتدار پر مسلط رکھنا چاہتا ہے جبکہ امریکہ ظاہر شاہ کی شکل میں اپنا نجیب اللہ مسلط کرنے کی کوشش میں ہے۔ لیکن افغان مجاہدین کے لیے، جو افغانستان کو ایک خالص اسلامی نظریاتی ریاست بنانے اور مکمل شرعی نظام نافذ کرنے کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، یہ دونوں ناقابل قبول ہیں اور وہ ان دونوں کو مسترد کرتے ہوئے مکمل کامیابی کے حصول تک جہاد جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔
افغان مجاہدین یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں روسی اثر و نفوذ کا دروازہ ظاہر شاہ نے ہی اپنے اقتدار میں کھولا تھا اور ایسی پالیسیوں کا آغاز کیا تھا جو بالآخر افغانستان پر روسی افواج کے تسلط پر منتج ہوئیں۔ اور جب افغان عوام مسلسل گیارہ سال تک روسی افواج کی جارحیت کے خلاف لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، ظاہر شاہ نے عسکری، سیاسی یا سفارتی کسی محاذ پر کوئی رول ادا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس لیے ظاہر شاہ کو نئی صورتحال میں کوئی کردار سونپنا افغان عوام کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان مجاہدین کا یہ موقف حقیقت پسندانہ ہے اور ایک غیرت مند قوم کے شایانِ شان بھی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کی باغیرت اور حریت پسند اقوام کو اس موقف کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔
انکارِ حدیث کا عظیم فتنہ
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
مذہبی لحاظ سے سطحِ ارض پر اگرچہ بے شمار فتنے رونما ہو چکے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور تا قیامت باقی رہیں گے لیکن فتنۂ انکارِ حدیث اپنی نوعیت کا واحد فتنہ ہے۔ باقی فتنوں سے تو شجرِ اسلام کے برگ و بار کو ہی نقصان پہنچتا ہے لیکن اس فتنہ سے شجرِ اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور اسلام کا کوئی بدیہی سے بدیہی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم فتنہ کے دست برد سے عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات، معیشت و معاشرت اور دنیا و آخرت کا کوئی اہم مسئلہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا حتٰی کہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بھی کچھ کی کچھ ہو کر رہ گئی ہے اور اس فتنہ نے اسلام کی بساطِ کن الٹ کر رکھ دی ہے جس سے اسلام کا نقشہ ہی بدل چکا ہے، سچ ہے
ستم کیشی کو تیری کوئی پہنچا ہے نہ پہنچے گا
اگرچہ ہو چکے ہیں تجھ سے پہلے فتنہ گر لاکھوں
نزولِ وحی کے زمانہ سے لے کر تقریباً پہلی صدی تک صحیح احادیث کو بغیر کسی تفصیل کے متفقہ طور پر حجت سمجھا جاتا تھا اور حسبِ مراتب عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات وغیرہا میں قرآن کریم کے بعد احادیثِ صحیحہ سے بلاچون چرا استدلال و احتجاج درست سمجھا جاتا تھا اور احادیث کو دینی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا۔ حتٰی کہ بعض فتنہ گھر اور خواہش زدہ فرقے ظاہر ہوئے جن میں پیش پیش معتزلہ تھے جن کا پیشواءِ اول واصل بن عطاء المتولد ۸۰ھ تھا جن کے نزدیک دلائل و براہین کی مد میں ایک سب سے بڑا معیار و مقیاس عقل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے راحتِ قبر و عذابِ قبر، حشر نشر کے بعض حقائق، رؤیت باری تعالیٰ، شفاعت، صراط و میزان اور جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ کے بہت سے حقائقِ ثابتہ اور کیفیات کو اپنی عقلِ نارسا کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی خام عقل کی ترازو سے تولنا چاہا اور راہِ راست سے بھٹک کر ورطۂ ضلالت میں اوندھے منہ گر پڑے اور اس سلسلہ میں داروشدہ تمام احادیث کو ناقابلِ اعتبار قرار دے کر یوں گلوخلاصی کی ناکام اور بے جا سعی کی، اور جن کا آسانی سے انکار نہ کر سکے ان کی نہایت ہی لچر اور رکیک تاویلات شروع کر دیں تاآنکہ بعض قرآنی حقائق اور نصوصِ قطعیہ بھی ان کی دوراَزکار اور لاطائلِ تاویلات سے محفوظ نہ رہ سکے جو بزبان حال ان کی اس تحریف کی وجہ سے ان پر لعنت کا تحفہ بھیجتے ہیں۔
معتزلہ اور ان کے بہی خواہوں کے علاوہ باقی سب اسلامی (یا منسوب بہ اسلام) فرقے صحیح احادیث کو برابر حجت تسلیم کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث حافظ ابن حزمؒ (المتوفی ۴۵۶ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت، خوارج، شیعہ اور قدریہ تمام فرقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو ثقہ راویوں سے منقول ہوں، برابر حجت تسلیم کرتے رہے۔ یہاں تک کہ پہلی صدی کے بعد متکلمین معتزلہ آئے اور انہوں نے اس اجماع کے خلاف کیا (الاحکام ج ۱ ص ۱۱۴ لابن حزمؒ)۔ اس کے بعد یہ مہلک فتنہ رفتہ رفتہ اپنا نطاق اور حلقہ وسیع کرتا چلا گیا اور بہت سے بندگانِ خواہشات و ہواء اس فتنہ کے دام ہم رنگ زمین میں الجھ کر رہ گئے اور یوں اپنی عاقبت برباد کر دی۔ نعوذ باللہ من سوء العاقبۃ۔
کتابی شکل میں اس فتنہ کی خبر سب سے پہلے مقتداء اہلسنت حضرت امام شافعیؒ (المتوفی ۲۰۴ھ) نے اپنے رسالہ اصولِ فقہ میں لی ہے جو ان کی مشہور کتاب ’’الاُم‘ کی ساتویں جلد کے ساتھ منضم اور بہت مفید اور مدلدل رسالہ ہے۔
حضرت امام احمد بن حنبلؒ (المتوفی ۲۴۱ھ) نے بھی اطاعتِ رسول کے اثبات میں ایک مستقل کتاب لکھی اور قرآن و حدیث سے مخالفین کی خوب معقول تردید کی ہے، جس کا کچھ حصہ حافظ ابن القیمؒ (المتوفی ۷۵۱ھ) نے اپنی تالیف اعلام الموقعین (جلد ۲ ص ۲۱۷) میں نقل کیا ہے۔
علماء اہل مغرب میں سے شیخ الاسلام ابوعمر ابن عبد البرؒ (المتوفی ۴۶۳ھ) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ’’جامع بیان العلم وفضلہ‘‘ میں اس فرقے کے بعض باطل اور حیاسوز نظریات کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیری ہیں۔ ایسے ہی بعض بدباطن اور رایفین سے امام حاکمؒ (المتوفی ۴۰۵ھ) کو بھی سابقہ پڑا تھا جن کی شکایت انہوں نے ’’مستدرک‘‘ ج ۱ ص ۳ میں کی ہے کہ وہ رواتِ حدیث پر سبّ و شتم کرتے اور ان کو موردِ طعن قرار دیتے ہیں۔ اور علامہ ابن حزمؒ نے ’’الاحکام‘‘ میں اس باطل گروہ کے کاسد خیالات کے بخیئے ادھیڑے ہیں اور ٹھوس عقلی اور نقلی دلائل سے ان کا خوب رد کیا ہے۔ اور امام غزالیؒ (المتوفی ۵۰۵ھ) نے اپنی معروف تصنیف ’’المستصفٰی‘‘ میں اس گمراہ طائفے کے مزعومہ دلائل کے تاروپود بکھیر کر رکھ دیے اور عقلی دلائل کے بے پناہ سیلاب میں اس گمراہ کن ٹولہ کے خودساختہ براہین کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم وزیریمانیؒ المتوفی (۸۴۰ھ) نے اس حزب باطل کی تردید میں اپنی انوکھی تالیف ’’المروض الباسم‘‘ میں کافی وزنی اور ٹھوس دلائل پیش کیے ہیں۔ اور حضرت امام سیوطیؒ (المتوفی ۹۱۱ھ) نے بھی اس ناپاک فرقہ کی ’’مفتاح الجنۃ فی الاحتجاج بالسنۃ‘‘ میں خوب تردید کی ہے اور دینِ قویم کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔
ان کے علاوہ بھی متعدد علمائے حق نے حدیث کے حجیّت ہونے اور نہ ہونے کے مثبت اور منفی پہلو پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اس باطل اور گمراہ کن نظریہ کی کہ ’’حدیث حجیّت نہیں ہے‘‘ اچھی خاصی تردید کی ہے اور معقول و مبنی بر انصاف دلائل کے ساتھ حق اور اہلِ حق کی طرف سے مدافعت کی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں باطل کے مقابلہ میں حق تعالیٰ نے کچھ ایسے نفوسِ قدسیہ پیدا کئے ہیں جن کی علمی و عملی، اخلاقی و روحانی زندگی حق پسند لوگوں کے لیے مشعلِ راہ اور مخالفین کے باطل خیالات کے لیے سدّسکندری بنتی رہی ہے جن کے قلموں اور زبانوں نے تلواروں اور نیزوں کی طرح باطل پرستوں کے پیش کردہ دلائل کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے اور قبائے باطل کے ایسے بخیئے ادھیڑے ہیں کہ تمام ’’رفوگر‘‘ مل کر بھی ان کو جوڑنے سے رہے۔ سچ ہے ’’لِکُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوْسٰی‘‘۔ علامہ اقبال کی زبان سے
شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک غیر اللہ کی
خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گرِ باطل بھی تو
قرآنِ کریم نے موجودہ بائبل کی تصدیق نہیں کی
پادری کے ایل ناصر کی فریب کاریوں کے جواب میں
حافظ محمد عمار خان ناصر
قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سراسر سچائی اور حقانیت پر مبنی ہے اور دنیا کے کسی بھی مذہب اور گروہ کے حقیقت پسند افراد کے لیے قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق سے انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم سے قبل بھی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں جن میں بڑی اور مشہور تین ہیں: تورات، زبور اور انجیل۔ یہ کتابیں بھی قرآن کریم کی طرح سچی تھیں لیکن آج اپنی اصل صورت میں نہیں پائی جاتیں کیونکہ ان کے ماننے والوں نے ان میں لفظی و معنوی تحریف کر کے ان کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا اور آج ان کے نام پر جعلی اور فرضی کتابیں عیسائیوں کے پاس ’’بائبل‘‘ کے نام سے موجود ہیں۔
ان کتابوں کے ضمن میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ سب کتابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں اور ان میں بیان کردہ امور حقیقت اور سچائی سے عبارت تھے لیکن آج ان میں تحریف ہو چکی ہے اور وہ بعینہٖ محفوظ نہیں رہیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی ان کتابوں کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں اور قابلِ عمل نہیں رہے۔ قرآن کریم نے اسی معنی میں ان کتابوں کی تصدیق کی ہے لیکن بعض مسیحی علماء قرآن پاک کی طرف سے کتب سابقہ کی تصدیق کو غلط معنی پہنا کر موجودہ بائبل کو صحیح اور قرآن کریم کی تصدیق شدہ ثابت کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ چنانچہ مسیحی پادری صاحبان کے اس گینگ کے معروف سرغنہ ڈاکٹر کے ایل ناصر نے اپنی کتاب ’’تصدیق الکتاب‘‘ میں جہاں مرزا ناصر احمد کے چیلنج کا جواب دیا ہے وہاں اس مسئلہ پر بھی سعیٔ لاحاصل کی ہے اور قرآن کریم کی آیات کی خودساختہ تعبیر و تشریح کی ہے، جبکہ اس غیر دیانتدارانہ روش کو خود مسیحی علماء نے بھی ناپسند کیا ہے۔
چنانچہ پادری ناصر صاحب کے ایک ہم نوا وکلف اے سنگھ صاحب رقم طراز ہیں:
’’تبلیغِ دین یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے مسلّمات و عقاید یا کتب مقدسہ کی بلاتحقیق من مانی تفسیر کی جائے بلکہ یہ کہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ بے شک اپنے مذہب کی صداقت و تائید کے لیے دیگر کتب سماوی سے حوالے دینا جائز تو ہے لیکن درست تفسیر اور درست نیت کے ساتھ یہی مذہب کا مقصد ہے اور یہی تبلیغِ دین۔‘‘ (رسالہ ’’فارقلیط ص ۷)
اس عبارت میں وکلف صاحب نے وہ جاندار اصول بیان کیا ہے جس پر پادری صاحبان عمل پیرا نہیں ہو سکتے اور یہی رویہ کے ایل ناصر نے اپنی مذکورہ کتاب میں اپنایا ہے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا۔ ہم ان کے پیش کردہ دلائل میں سے بعض ضروری دلیلوں کا جائزہ لینے سے قبل مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں:
امرِ اول
عیسائیوں میں دو فرقے مشہور ہیں: (۱) کیتھولک (۲) پروٹسٹنٹ۔اسی طرح یہودیوں میں ایک فرقہ اپنے مخصوص اعمال و عقائد کی وجہ سے معروف ہے یعنی فرقہ ’’سامریہ‘‘۔ پروٹسٹنٹ فرقہ اور عام یہودیوں کی بائبل ایک ہے اگرچہ تقسیم میں اختلاف ہے۔ اور کیتھولک بائبل میں سات کتابیں زائد ہیں جبکہ فرقہ سامریہ کی بائبل میں صرف سات کتابیں ہیں۔ یاد رہے کہ یہودی بائبل کے عہدنامہ جدید کو الہامی نہیں مانتے کیونکہ حضرت عیسٰیؑ کی نبوت کا انکارکرتے ہیں۔
اس وضاحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بائبل اس وقت تین مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ اب یہ پادری صاحب ہی جانتے ہوں گے کہ نبی کریمؐ کے زمانے میں کونسی بائبل موجود تھی، قرآن نے کس کی تصدیق کی؟ واضح رہے کہ پادری صاحب کیتھولک بائبل میں موجود سات زائد کتابوں کے الہام کے قائل نہیں ہیں اور فرقہ سامریہ باقی یہود کی بائبل کی تحریف مانتا ہے۔ (بحوالہ الملل والنحل لابن حزم الظاہریؒ)
امرِ دوم
اہلِ کتاب اور اہلِ اسلام کے درمیان اصول تنزیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن پاک کے مطابق تورات اسلام سے تختیوں پر لکھی لکھائی حضرت موسٰیؑ کو کوہِ طور پر ملی۔ انجیل کے بارے میں گو قرآن میں اس قسم کی تصریح نہیں ہے کہ وہ کس صورت میں ان کو ملی البتہ انجیل کے یکبارگی نازل ہونا قرآن سے معلوم ہوتا ہے جبکہ عیسائیوں کے نزدیک یہ اصول معتبر نہیں ہے۔ اسی بات کی وضاحت میں پادری برکت اے خان رقم طراز ہیں:
’’مسیحیوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آسمان پر سے لکھی ہوئی توریت کی کتاب، زبور کی کتاب، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس نازل ہوئی تھیں۔‘‘ (اصول تنزیل الکتاب ص ۹)
اور پادری طالب شاہ آبادی ’’سرچشمۂ قرآن‘‘ میں لکھتے ہیں کہ
’’ہم مسیحی کلامِ الٰہی کے کسی خاص زبان میں بصورت کتاب آسمان سے نازل ہونے کے قائل نہیں ہیں۔‘‘ (بحوالہ سہ ماہی ’’ہما‘‘ لکھنو ۔ ص ۴ ۔ اکتوبر دسمبر ۱۹۶۷ء)
اور وکلف اے سنگھ صاحب فرماتے ہیں کہ
’’دراصل حضور المسیح پر کوئی انجیل ہی نازل نہیں ہوئی جیسا کہ اہل اسلام میں مشہور ہے۔‘‘ (رسالہ ’’غلط فہمیاں‘‘ ص ۳۰)
مسیحی علماء کے ان اقوال سے واضح ہو چکا ہے کہ عیسائی تورات کے بارہ میں قرآن کے اصولِ تنزیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب پادری ناصر صاحب بتلائیں کہ کیا انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ان کے پاس جو تورات ہے وہ وہی ہے جس کی تصدیق قرآن نے کی ہے؟
امرِ سوم
قرآن پاک اور موجودہ بائبل کے درمیان واقعات و عقائد اور بہت سے امور میں اختلاف ہے مثلاً:
(۱) قرآن کریم کی رو سے آدم علیہ السلام کو ان کی زلّت (لغزش) پر ان کی حیات میں ہی معافی مل گئی تھی جبکہ بائبل کہتی ہے کہ یہ گناہ اس وقت دھلا جب عیسٰیؑ المسیح نے سولی پر جان دے دی۔
(۲) قرآن مجید کے نزدیک حضرت موسٰیؑ سے قتل کا فعل عمدًا صادر نہیں ہوا تھا جبکہ بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے پہلے ادھر ادھر چیک کیا کہ کوئی اور تو نہیں ہے اس کے بعد اس کو قتل کر کے ریت میں چھپا دیا۔
(۳) قرآن پاک میں نص صریح ہے کہ حضرت عیسٰیؑ مصلوب یا مقتول نہیں ہوئے جبکہ چاروں اناجیل کے آخر میں ’’واقعہ تصلیب‘‘ مذکور ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کو بائبل کا مصدق نہیں ہونا چاہیئے، حالانکہ پادری صاحب ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔
امرِ چہارم
قرآن حکیم کی تعلیم سراسر اخلاقی ہے اور بے حیائی اور گندگی سے بالکلیۃ محفوظ ہے۔ نہ تو اس میں انبیاء علیہم السلام کے کردار پر کوئی کیچڑ اچھالا گیا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کے بارے میں ناقابلِ قبول اور رذیل تصور دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس بائبل اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں ہم نمونے کے طور پر چند واقعات کے حوالجات تحریر کرتے ہیں:
- حضرت نوح ؑ کا شراب پی کر ڈیرے میں برہنہ ہونا۔ (پیدائش ۹ : ۲۰، ۲۱)
- حضرت لوط ؑ کا اپنی دو بیٹیوں سے زنا کرنا۔ (پیدائش ۱۹ : ۳۱ تا ۳۸)
- حضرت داؤدؑ کا اپنی پڑوسن سے زنا کرنا۔ (۲ ۔ سموئیل ۱۱ : ۲ تا ۵۲)
- حضرت سلیمانؑ کی بت پرستی۔ (۱۔ سلاطین ۱۱ : ۱ تا ۶)
- حضرت ہوسیعؑ کا خدا کے حکم سے ایک کنجری سے جماع کرنا۔ (ہوسیع ۱ : ۲، ۳)
- حضرت سمسونؑ کا اجنبی شہر میں ایک کسبی کے ساتھ شب باشی کرنا۔ (قضاۃ ۱۶ : ۱، ۲)
- حضرت یعقوبؑ کے لڑکے یہودا کا اپنی بہو سے زنا کرنا۔ (پیدائش ۳۸ : ۱۵ تا ۱۸)
- خدا کا ملول ہونا۔ (پیدائش ۶ : ۶)
- خدا کا کشتی میں ہار جانا۔ (پیدائش ۳۲ : ۲۳ تا ۳۲)
- خدا کا میدانِ جنگ میں شکست کھانا۔ (قضاۃ ۱ : ۱۹)
- خدا کا کرایہ پر استرا لے کر داڑھی مونڈنا۔ (یسعیاہ ۷ : ۲۰)
- خدا کا لڑکی کو پالنا اور اس پر عاشق ہونا۔ (حزقی ایل ۱۶ : ۱ تا ۴)
- خدا کی دو بدکار عورتوں سے یاری۔ (حزقی ایل ۲۳ : ۱ تا ۲۱)
- خدا کی کمزوری و بیوقوفی (کرنتھیوں ۱ : ۲۵)
یہ تمام حوالہ جات بائیبل کے تقدس کے ڈھول کا پول کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تو گویا پادری ناصر نے یہ دعوٰی کر کے کہ قرآن کریم بائبل کا مصدق ہے قرآن پاک پر صریح بہتان لگایا ہے۔
امرِ پنجم
قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ لفظ بہ لفظ صحیح اور اصلی حالت میں بغیر کسی تغیر و تبدل کے ہم تک پہنچا ہے اور اس کی کوئی سورت یا آیت یا کوئی لفظ یا حرف ضائع نہیں ہوا۔ اس کے برعکس بائبل میں مختلف مقامات پر چند ایسی کتابوں کا ذکر ملتا ہے جو گم شدہ ہیں اور آج نہیں پائی جاتیں۔ یہاں پر ان کی کتابوں کی فہرست دی جاتی ہے۔
(۱) کتاب عہد نامہ موسٰیؑ (خروج ۲۴ : ۷)
(۲) کتاب جنگ نامہ موسٰیؑ (گنتی ۲۱ : ۱۴)
(۳) کتاب السییر (۲۔ سموئیل ۱ : ۱۸ ۔ ویشوع ۱۰ : ۱۳)
(۴) کتاب یاحو پیغمبر بن ضانی (۲۔ تواریخ ۲۰ : ۳۴)
(۵) کتاب شمعیاہ نبی (۲۔ تواریخ ۱۲ : ۱۵)
(۶) کتاب اخیاہ نبی (۲۔ تواریخ ۹ : ۲۹)
(۷) کتاب ناتن نبی (۲۔ تواریخ ۹ : ۲۹)
(۸) کتاب مشاہدات عید و غیب بینی (۲۔ تواریخ ۹ : ۲۹)
(۹) کتاب اعمال سلیمانؑ (۱۔ سلاطین ۱۱ : ۴۱)
(۱۰) کتاب مشاہدات یسعیاہ (۲۔ تواریخ ۳۲ : ۳۲)
(۱۱) کتاب اشعیاء بن عاموس (۲۔ تواریخ ۲۶ : ۲۲)
(۱۲) سموئیل نبی کی تاریخ (۱۔ تواریخ ۲۹ : ۲۹، ۳۰)
(۱۳) سلیمانؑ کی زبور (۱۔ سلاطین ۴ : ۳۲، ۳۳)
(۱۴) کتاب خواص نباتات و حیوانات سلیمانؑ کی (۱۔ سلاطین ۴ : ۳۲)
(۱۵) کتاب اقبال سلیمان (۱۔ سلاطین ۴ : ۳۲)
(۱۶) جادو غیب بین کی تاریخ (۱۔ تواریخ ۲۹ : ۲۹)
(۱۷) مرثیہ ہرسیاہ (۲۔ تواریخ ۳۵ : ۲۵)
(ماخوذ از ’’نوید جاوید‘‘ ص ۱۳۷ و ۱۳۸)
ہم پادری صاحب سے یہ پوچھنے کا حق ضرور رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں کہاں گئیں اور کیوں گم ہوئیں اور نبی کریمؐ کے زمانے میں یہ بھی مروّج تھیں یا نہیں؟ اور کیا قرآن پاک نے ان کی تصدیق بھی کی ہے یا نہیں؟ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ
(۱) یقرؤن الکتٰب من قبلک۔ (یونس ۹۴)۔ ترجمہ: ’’پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے والی‘‘۔ میں الکتاب سے مراد (پوری) بائبل ہے اور اس سے موجودہ بائبل کی آنحضرت[ کے زمانے میں موجودگی کا پتہ چلتا ہے کیونکہ قراءت موجودہ و حاضر کتاب کی ہوتی ہے۔ (ملخصًا)
اس آیت میں ’’الکتاب‘‘ سے مراد پادری صاحب نے جو بائبل یعنی توریت، صحائف، زبور، اناجیل اور خطوط وغیرہ لیا ہے وہ غلط ہے، آیت کے سیاق و سباق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد صرف توریت ہے نہ کہ ساری بائبل۔
(۲) کے ایل ناصر صاحب نے قرآن کریم کی آیت ’’من اھل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ‘‘ کو نقل کر کے ’’آیات اللہ‘‘ سے مراد بائبل لیا ہے اور کہا ہے کہ ’’امۃ قائمۃ‘‘ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مراقبہ میں قابلِ نمونہ تھے۔ جبکہ اس آیت میں آیات اللہ سے مراد قرآن پاک ہے اور امۃ قائمۃ ایمان لانے والے اہلِ کتاب کو کہا گیا ہے، اور پادری صاحب نے حسبِ عادت تحریفِ معنوی کرتے ہوئے اس آیت کی غلط تفسیر کی ہے۔
(۳) سورہ نساء کی آیت ’’اٰمنوا باللہ ورسولہ والکتٰب الذی نزل علٰی رسولہ والکتٰب الذی انزل من قبل‘‘ کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ بائبل پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کتنی ضروری ہے۔ لیکن پادری صاحب نے غور نہ کیا کہ یہاں ’’الکتٰب‘‘ سے مراد اگرچہ تمام انبیاء کی کتابیں ہیں لیکن نزول کا لفظ بھی ساتھ مذکور ہے جس سے اہلِ اسلام کا وہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے جس کا پادری برکت صاحب نے سختی سے انکار کیا ہے یعنی توریت کا لکھی لکھائی خاص زبان میں نزول۔
(۴) سورہ مائدہ کی آیت ۶۸ یوں ہے ’’یا اھل الکتٰب لستم علٰی شیء حتٰی تقیموا التورٰۃ والانجیل‘‘ اس آیت کی وجہ سے پادری صاحب کا یہ استدلال باطل ہو جاتا ہے کہ ’’الکتٰب‘‘ سے مراد قرآن پاک میں بائبل ہے کیونکہ یہاں اہلِ کتاب کے مقابلے میں تورات اور انجیل کا لفظ لایا گیا ہے یعنی کتاب سے مراد توریت و انجیل ہے نہ کہ موجودہ بائبل، اور انجیل بھی وہ جو ایک تھی نہ کہ چار مختلف انجیلیں۔
یہ وہ آیات تھیں جن سے پادری صاحب نے بائیبل کا حضور[ کے زمانہ میں موجود و مروّج ہونا ثابت کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بعض آیات کی تفسیر میں فاش غلطیاں کیں۔ ان کے علاوہ بھی انہوں نے متعدد آیات نقل کی ہیں۔ قرآنی آیات کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے چند احادیث نقل کی ہیں جن سے انہوں نے بائیبل کا آنحضرتؐ کے زمانے میں موجود ہونا ثابت کیا ہے، آئیے ذرا ان پر بھی نظر ڈال لی جائے۔
پادری صاحب موصوف نے مشکٰوۃ شریف کے حوالہ سے صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔
ہمارے نزدیک اس آیت سے موجودہ بائبل کا اس زمانے میں وجود کا استدلال کرنا جہالت ہے اور پادری صاحب خود بھی اس کتاب کے ص ۴۲ پر یہ تفسیر فرما چکے ہیں کہ تورات سے مراد پانچ صحیفے ہیں یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء اور مسیحیوں کے نزدیک ان پانچ صحائف کو بائبل نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح مشکٰوۃ ہی میں یہ روایت ہے کہ حضورؐ نے یہود و نصارٰی کے تورات و انجیل کے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرتؐ کے سامنے تورات پڑھی تو حضورؐ ناراض ہوئے۔ جبکہ پادری صاحب ان احادیث سے جن میں توراۃ کا لفظ ہے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ عبرانی بائبل اور عربی بائبل ہی موجود تھی۔ اور اسی طرح تورات سے مراد بائبل لیتے ہوئے انہوں نے چند آیات نقل کی ہیں جن میں خدا کی جانب حضرت موسٰیؑ کو کتاب دینے اور ان پر نازل کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح وہ آیات بھی ذکر کی ہیں جن میں زبور اور انجیل کے بارے میں اتارنے اور انبیاء کو دینے کا تذکرہ ہے۔ الغرض پادری صاحب کی یہ کتاب غلطیوں اور خرافات کا مجموعہ ہے۔ کتاب کے ص ۵۱ تک تو قرآنی آیات کے بیان اور ان کی من مانی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے آگے انہوں نے چند روایات و اقوال کو نقل کر کے اپنے زعم میں چونکا دینے کی کوشش کی ہے۔
امام رازیؒ کی تفسیر کبیر اور امام سیوطیؒ کی تفسیر درمنشور سے انہوں نے چند روایات کو نقل کیا ہے جن میں صراحت ہے کہ توریت و انجیل کے حروف و الفاظ بدلے نہیں گئے۔ یہ بھی پادری صاحب کی مغالطہ نوازی ہے کیونکہ مفسرین کسی آیت کی تفسیر میں جو کچھ نقل کرتے ہیں وہ سب ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوتا۔ مفسرین کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی آیت کے ضمن میں جتنے اقوال ان کے علم میں ہوتے ہیں وہ سب نقل کر دیتے ہیں جو بعض اوقات متضاد بھی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی مفسر نے جو بات کسی آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے وہ اس کے نزدیک صحیح بھی ہے۔ چنانچہ جناب محمد اسلم رانا اس کی وضاحت میں یوں لکھتے ہیں:
’’قرآن کریم کے قدیم مفسرین کسی مسئلہ پر لکھتے وقت موافق و مخالف دونوں اقسام کے اقوال بلا کم و کاست بیان کر دیتے تھے۔ وہ جس نظریہ کو درست سمجھتے اس کے دلائل زیادہ پھیلا کر لکھتے، بصورتِ دیگر اپنی رائے کا برملا اظہار آخر میں کرتے۔ تفاسیر میں غلط، صحیح، رطب، یابس، ہر قسم کے اقوال و آراء اور روایات مرقوم ہوتی ہیں۔ مفسر درج ضرور کرتا ہے لیکن ان سب کو صحیح نہیں سمجھتا۔‘‘ (طب و صحت ص ۱۴)
ہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ایک قول پادری صاحب نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے:
’’اما تحریف لفظی در ترجمہ توریت و امثال آں بکار می بردند نہ دراصل توریت پیش ایں فقیہہ ایں چنیں محقق شد و ھو قول ابن عباسؓ‘‘۔ (الفوز الکبیر ص ۷)
ترجمہ: ’’تحریف لفظی تو توریت اور اس جیسی دوسری کتابوں کے ترجمہ میں کرتے تھے نہ کہ اصل توریت میں، میرے نزدیک یہی محقق بات ہے اور یہ ابن عباسؓ کا قول ہے۔‘‘
پادری صاحب نے ترجمہ سے مراد تفسیر لیا ہے اور شاہ صاحبؒ کے قول سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف تحریف معنوی کے قائل ہیں حالانکہ شاہ صاحبؒ کا یہ مسلک نہیں ہے کیونکہ وہ خود دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:
’’ضلالت ایشاں تحریف احکام توریت بود خواہ تحریف لفظی باشد خواہ تحریف معنوی و کتمان آیات و افترا بالحاق آنچہ ازاں بآں۔‘‘
ترجمہ: ’’یہود کی گمراہی کا بیان یہ ہے کہ یہ توریت کے احکام کی تحریف کرتے تھے خواہ تحریف لفظی ہو خواہ معنوی (یعنی دونوں طریقوں سے) اور آیات (یعنی احکام) چھپاتے تھے اور وہ چیز اس میں الحاق کرتے تھے جو اس میں سے نہیں ہے۔‘‘
اور آگے جا کر فرماتے ہیں کہ
’’جواب اشکال اوّل برتقدیر تسلیم آنکہ کلام حضرت عیسٰی باشد نہ محرف آنست کہ لفظ ابن در زمان قدیم بمعنی محبوب و مقرب و مختار بودہ است۔‘‘ (ص ۱۰)
ترجمہ: ’’پہلے اشکال کا جواب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بیٹے کا لفظ حضرت عیسٰیؑ ہی کا ہے اور محرف نہیں ہے، یہ ہے کہ بیٹے کا لفظ پرانے زمانہ میں محبوب، مقرب اور پسندیدہ کے معنی میں ہوتا تھا۔‘‘
اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پادری صاحب حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی طرف جس بات کو منسوب کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ باقی رہی وہ عبارت جس میں ابن عباسؓ کا حوالہ ہے تو پادری صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تورات جن الواح پر لکھی ہوئی اتری تھی ان میں تو تحریف ناممکن تھی یعنی ان میں الفاظ کی زیادتی اور کمی وغیرہ ممکن نہیں تھی، لہٰذا جب وہ اس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے تھے تو تحریف لفظی کر دیا کرتے تھے اور یہی شاہ صاحبؓ کا مطلب ہے۔ پادری صاحب بتائیں کہ آپ کیتھولک کلیسا سے کیوں الگ ہوئے؟ کیونکہ ان کے پوپ اور پادری خود ہی سب کچھ کرتے تھے اور عوام کو کتاب مقدس پڑھنے سے روکتے تھے۔ آپ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل عبرانی بائبل ہے تو ہمیں عبرانی زبان کو صحیح طور سے سمجھنے والوں کی تعداد گنوا دیں۔ اور ابن عباسؓ کی طرف بھی وہ قول منسوب نہیں کیا جا سکتا جو پادری صاحب شاہ ولی اللہؒ کے قول سے اخذ کیے بیٹھے ہیں کیونکہ بخاری شریف میں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنھم سے یہ روایت موجود ہے:
ان عبد اللہ بن عباس قال یا معشر المسلمین کیف تسألون اھل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل اللہ علّی نبیکم احدث الاخبار باللہ محضًا لم یثب وقد حدثکم اللہ ان اھل الکتاب قد بدّلوا من کتب اللہ وغیروا فاکتبوا بایدیھم الکتب قالوا ھو من عند اللہ لیشتروا بہ شفًا قلیلًا اولا ینھاکم ما جاءکم من العلم ان مسألتھم ولا واللہ ما رأینا اجلًا منھم یسألکم عن الذی انزل علیکم۔ (بخاری ج ۲ ص ۱۱۲۲)
تو اس حدیث میں صراحت ہے کہ ابن عباسؓ نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ اہلِ کتاب سے کوئی سوال نہ کریں کیونکہ قرآن کے مطابق انہوں نے تحریف و تبدیلی کی۔
قارئین! اس جامع بحث میں ہم نے پادری کے ایل ناصر کے اس دعوٰی کا تاروپود بکھیر دیا ہے کہ قرآن پاک موجودہ بائبل کا تصدیق کنندہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیش کردہ دلائل بھی جواب کے محتاج نہیں تھے لیکن ہم نے پادری صاحب کے پیش کردہ ضروری دلائل پر قلم اٹھایا تاکہ وہ خواہ مخواہ کی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ ہمارا مقصد قطعًا توریت و انجیل کی اہانت نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ان کتابوں کو نور و ہدایت کے القاب دیے گئے ہیں لیکن جیسا کہ مقالہ سے واضح ہے کہ پادری صاحب کے اس زعم کو ہم نے توڑا ہے کہ قرآن پاک موجودہ بائبل کی تصدیق کرتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے خالصتًا انصاف سے کام لیا ہے، فللہ الحمد لٰی ذٰلک۔
عورت کی حکمرانی کی شرعی حیثیت
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
مرد اور عورت دونوں نسل انسانی کے ایسے ستون ہیں کہ جن میں سے ایک کو بھی اس کی جگہ سے سرکا دیا جائے تو انسانی معاشرہ کا ڈھانچہ قائم نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کو اپنی قدرت خاص سے پیدا فرمایا اور ان دونوں کے ذریعے نسل انسانی کو دنیا میں بڑھا پھیلا کر مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں اور فرائض کی فطری تقسیم کر دی، دونوں کا دائرہ کار متعین کر دیا اور دونوں کے باہمی حقوق کو ایک توازن اور تناسب کے ساتھ طے فرما دیا۔
مرد اور عورت کے درمیان حقوق و فرائض کی اس تقسیم کا تعلق تکوینی امور سے بھی ہے جو نسل انسانی کی تخلیق کے ساتھ ہی طے کر دیے گئے ہیں اور ان میں انسان کوشش بھی کرے تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مثلاً مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت و جاہ، جرأت و بہادری اور سختی و مضبوطی کا پیکر بنایا ہے جبکہ عورت اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے اس کے برعکس ہے، اس میں ملائمت ہے، انفعال ہے، کمزوری ہے اور کسی مضبوط پناہ کے حصار میں رہنے کا فطری جذبہ ہے۔ یہ ایک ایسا واضح فرق ہے جو زندگی کے تمام افعال و احوال میں جاری و ساری نظر آتا ہے اور جسے کوئی منطق، کوئی سائنس اور کوئی خودساختہ معاشرتی فلسفہ تبدیل نہیں کر سکتا۔
نسل انسانی کی نشوونما کے لیے خالقِ کائنات نے مرد اور عورت کے جنسی ملاپ کو ذریعہ بنایا اور اس ملاپ کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے دونوں میں محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ مرد اور عورت کے درمیان محبت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی بالادستی اور عورت کے انفعال کے فطری فرق کو قائم رکھا اور ملاپ میں بھی مرد کو بالادستی بخشی۔ یہ بھی ایسا واضح اور محسوس فرق ہے جس کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی منطقی یا سائنسی فارمولا کے ذریعے اسے بدلا جا سکتا ہے۔
نسل انسانی کو بڑھانے کے مشترکہ عمل میں بھی اللہ رب العزت نے دونوں کے فرائض الگ الگ متعین کر دیے۔ عورت کے ذمے بچہ کے بوجھ کو پیٹ میں اٹھانا، پیدائش کے بعد اس کو گود میں لینا اور ہوش سنبھالنے تک اس کی تمام چھوٹی موٹی ضروریات و حوائج خود سرانجام دینا ہے۔ جبکہ مرد کو ان تینوں کاموں سے رب العزت نے آزاد رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ باقی امور اس کے ذمہ ہیں کہ وہ بچہ اور اس کی ماں کے اخراجات کا بوجھ اٹھائے گا، ان کی حفاظت و نگرانی کرے گا اور معاشرہ کے ساتھ ان کے رابطہ و تعلق کا ذریعہ بنے گا۔ یہ فرق اور تقسیم بھی ایسی ٹھوس ہے کہ تبدیلی اور تغیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یورپی معاشرت نے عورت کی آزادی اور اس کے احترام کی بحالی کے نام سے اس فرق کو مٹانے کی سرتوڑ کوشش کی ہے لیکن اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ عورت کی ذمہ داریوں اور فرائض میں اضافہ ہوگیا ہے۔ عورت خود کو بچے کی پیدائش اور پرورش کے بوجھ سے تو آزاد نہیں کرا سکی البتہ اخراجات کی کفالت کی ذمہ داری میں مرد کے ساتھ شریک ہوگئی ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں یورپی معاشرت کے پیروکار مردوں نے مزید کسی ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر لیے بغیر اپنی ذمہ داریوں کا نصف بوجھ بھی عورت پر ڈال دیا ہے اور ناقص العقل سادہ عورت آزادیٔ مساوات اور زندگی کی دوڑ میں کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے خوشنما اور دلفریب نعروں سے دھوکا کھا کر دوہری ذمہ داریوں کے چکر میں پھنس کر رہ گئی ہے۔
اسلام ایک فطری نظامِ حیات ہے جو اسی خالق و مالک نے عطا فرمایا ہے جس نے مرد اور عورت کے درمیان فرائض و حقوق کی تکوینی تقسیم کی ہے، اسی لیے اسلام کے شرعی اور قانونی احکام کی بنیاد بھی اس تکوینی تقسیم کے فطری تقاضوں پر ہے۔ اور اس وقت دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جو عورت اور مرد کے درمیان حقوق و فرائض کی شرعی اور قانونی تقسیم دونوں کے تخلیقی فرق اور تکوینی ذمہ داریوں کے عین مطابق کرتا ہے اور اس کے ذریعے ایک خوشحال، پرسکون اور پر امن معاشرہ کی ضمانت دیتا ہے۔ ورنہ بیشتر مروجہ معاشرتی اقدار کی بنیاد اس فطری اور تکوینی فرق سے فرار اور انحراف پر ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرق تو کسی سے مٹ نہیں پا رہا مگر اس سے انحراف اور فرار پر مبنی معاشرتی بے چینی، نفسیاتی پیچیدگیوں اور ذہنی الجھنوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
یورپی تہذیب و معاشرت نے آزادی اور مساوات کے نام پر جہاں عورت کو اس غلط فہمی میں ڈالا کہ ملازمت کرنا اس کا حق ہے، حالانکہ ملازمت حق نہیں ذمہ داری ہے، اسی طرح حکمرانی اور قیادت کو حقوق کی فہرست میں شامل کر کے عورت کو اس دوڑ میں بھی شریک کر دیا۔ جبکہ اسلام اس فلسفہ کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر کے اخراجات فراہم کرنے کے لیے ملازمت کرنا حقوق سے نہیں بلکہ ذمہ داریوں سے تعلق رکھتا ہے، اور مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں کی فطری تقسیم میں یہ ذمہ داری مرد کے کھاتے میں ہے۔ اسی طرح حکمرانی اور قیادت کا شمار بھی حقوق میں نہیں بلکہ ذمہ داریوں اور فرائض میں ہوتا ہے اور اسلام عورت کے طبعی اور فطری فرائض اور ذمہ داریوں سے زائد کسی ذمہ داری اور فرض کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حکمرانی کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اور عورت کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ انسانی معاشرت کے اسلامی فلسفہ اور آج کے مروجہ نظریات میں یہی بنیادی فرق ہے کہ اسلام حکمرانی کو ذمہ داری قرار دیتا ہے جبکہ موجودہ سیاسی نظاموں نے اسے حقوق میں شامل کر کے اس خودساختہ حق کے لیے مختلف انسانی طبقات کو مسابقت کی دوڑ میں اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ حقوق و فرائض کے درمیان کوئی خطِ امتیاز باقی نہیں رہا۔
اس پس منظر میں جب ہم عورت کی حکمرانی کے بارے میں اسلام کے احکام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی منطق میں کوئی وزن دکھائی نہیں دیتا جو مغرب کی معاشرتی اقدار کو اپنے معاشرے پر منطبق کرنے کے شوق میں نہ صرف مرد اور عورت کے درمیان مساوات اور عورت کی نام نہاد آزادی کا پرچار کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے اسلام کے واضح احکام کو توڑ موڑ کر پیش کرنے اور انہیں خودساختہ معانی پہنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ چنانچہ ان دنوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک خاتون کی حکمرانی کے حوالہ سے یہ بحث چل رہی ہے کہ شرعاً کسی عورت کو حکمران بنانا درست ہے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن و سنت اور اجماع امت کی واضح تصریحات کے باوجود کچھ حضرات اس کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے عورت کی حکمرانی کے جواز میں دلائل کشید کیے جائیں تاکہ مغربی تہذیب و معاشرت کی پیروی کے شوق اور عمل کو شرعی جواز کی چھتری بھی فراہم کی جا سکے۔ اسی لیے یہ ضروری محسوس ہوا کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں شرعی احکام کو وضاحت کے ساتھ قارئین کے سامنے لایا جائے اور ان خودساختہ دلائل کی حقیقت بے نقاب کر دی جائے جو اس مسلمہ اجماعی مسئلہ کو مشکوک بنانے کے لیے مختلف حلقوں کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔
اسلام میں کسی بھی مسئلہ کے شرعی ثبوت کے لیے مسلمہ اصول چار ہیں جنہیں دلیل کے طور ر پیش کیا جاتا ہے۔
- قرآن کریم
- سنتِ نبویؐ
- اجماع امت
- اجتہاد و قیاس
ہم ترتیب کے ساتھ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں ان چاروں دلائل کو پیش کریں گے کہ کسی عورت کو حکمران بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔
(۱) قرآن کریم
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق و فرائض کی اس فطری تقسیم کو واضح کا ہے۔ ان سب آیات کریمہ کو اس موقف کے حق میں منطقی استدلال کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے لیکن ہم ان میں سے دو آیات کریمہ کا حوالہ دیں گے۔
(1) حکمرانی کا تصور اسلام میں ’’خلافت‘‘ کا ہے کہ انسانی معاشرہ میں کوئی بھی حکمران خودمختار نہیں بلکہ حکمرانی میں خدا تعالیٰ کا نائب ہے۔ اصل حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے اور انسان اس کا نائب ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق انسانی معاشرہ پر حکومت کرتا ہے، اسی کا نام ’’خلافت‘‘ ہے۔ جب تک انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہا، خلافت کا یہ منصب زیادہ تر حضرات انبیاء کرامؑ ہی کے پاس رہا۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے کتاب الامارۃ میں حضرت ابوہریرہؓ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا اظہار یوں فرمایا ہے کہ
’’بنی اسرائیل میں سیاسی قیادت کا فریضہ انبیاء کرام علیہم السلام سرانجام دیتے تھے، جب ایک نبیؑ دنیا سے چلے جاتے تو دوسرے نبیؑ ان کی جگہ لے لیتے۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔‘‘
یعنی خلافت و حکومت دراصل انبیاء کرامؑ کی نیابت کا نام ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صراحت کر دی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے وہ سب مرد تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْ اِلَیْھِمْ۔
’’اور ہم نے آپؐ سے قبل رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر صرف مردوں کو جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔‘‘
اس لیے جب نبی صرف اور صرف مرد آئے ہیں تو ان کی نیابت بھی صرف مردوں میں ہی محدود رہے گی۔
(2) اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:
اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَی النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰەُ بَعْضَھُمْ عَلٰی بَعْضٍ۔
’’مرد حکمران ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔‘‘
یہ آیت کریمہ اس بارے میں صریح ہے کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا مشترکہ معاملہ ہوگا وہاں حکمرانی مردوں ہی کے حصہ میں آئے گی اور یہی وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر عطا فرمائی ہے۔
اس آیت کریمہ کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ آیت کریمہ خاندانی احکام و قوانین کے سیاق و سباق میں ہے اس لیے اس سے مراد مطلق حکمرانی نہیں بلکہ خاندان کی سربراہی ہے جو ظاہر ہے کہ مرد ہی کے پاس ہے۔ لیکن ان کا یہ استدلال دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی روشنی میں جب ہم اس آیت کریمہ کا مفہوم متعین کریں گے تو اسے خاندان کی سربراہی تک محدود رکھنا ممکن نہیں رہے گا بلکہ خاندان کی سربراہی کے ساتھ مطلق حکمرانی بھی اس کے مفہوم میں شامل ہوگی۔ یہ ارشادات نبویؐ ہم آگے چل کر نقل کر رہے ہیں۔ دوسرا اس وجہ سے کہ امت کے معروف مفسرین کرامؒ نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی ہے اس میں علی الاطلاق ہر قسم کی حکمرانی عورت کے لیے نفی کی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:
ولھذا کانت النبوۃ مختصۃ بالرجال وکذلک الملک الاعظم وکذا منصب القضاء وغیر ذلک۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۹۱)
’’اور اسی وجہ سے نبوت مردوں کے ساتھ مخصوص ہے اور اسی طرح حکومت اور قضا کا منصب بھی انہی کے لیے خاص ہے۔‘‘
حافظ ابن کثیرؒ کے علاوہ امام رازیؒ (تفسیر کبیر ج ۱۰ ص ۸۸)، امام قرطبیؒ (ص ۱۶۸ ج ۵)، علامہ سید محمود آلوسیؒ (روح المعانی ص ۵ ص ۲۳) اور قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ (مظہری ج ۲ ص ۹۸) نے اس آیت کی یہی تفسیر لکھی ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی کم و بیش تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ سے عورت کی حکمرانی کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے۔
(۲) حدیث رسولؐ
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے ارشادات میں اس امر کی صراحت کی ہے کہ عورت کی حکمرانی نہ صرف عدم فلاح اور ہلاکت کا موجب ہے بلکہ مردوں کے لیے موت سے بدتر ہے۔ ان میں سے چند احادیث ذیل میں درج کی جا رہی ہیں:
(1) امام بخاریؒ کتاب المغازی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر دی گئی کہ فارس کے لوگوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے تو آنحضرتؐ نے فرمایا:
لَنْ یُّـفْلِحَ قَوْم وَّلَوْ اَمْرَھُمْ اِمْرَاَۃً۔
’’وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا۔‘‘
(2) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
’’جب تمہارے حکمران تم میں سے اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورہ سے طے پائیں تو تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکمران تم میں سے برے لوگ ہوں، تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔‘‘ (ترمذی ج ۲ ص ۵۲)
(3) امام حاکمؒ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے اور اس کی سند کو امام ذہبی نے صحیح تسلیم کیا ہے کہ جناب رسول اکرمؐ کی خدمت میں مسلمانوں کا ایک لشکر فتح و نصرت حاصل کر کے آیا اور اپنی فتح کی رپورٹ پیش کی۔ آنحضرتؐ نے مجاہدین سے جنگ کے احوال اور ان کی فتح کے ظاہری اسباب دریافت کیے تو آپؐ کو بتایا گیا کہ کفار کے لشکر کی قیادت ایک خاتون کر رہی تھی۔ اس پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ھَلَکَتِ الـرِّجَالُ حِـیْنَ اَطَاعَتِ النِّسَآءَ۔ (مستدرک حاکم ج ۴ ص ۲۹۱)
’’مرد جب عورتوں کی اطاعت قبول کریں گے تو ہلاکت میں پڑیں گے۔‘‘
(4) علامہ ابن حجر الہتیمیؒ حضرت ابوبکرؓ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرمؐ کی مجلس میں ملکہ سبا بلقیسؓ کا ایک دفعہ ذکر ہوا تو آنحضرتؐ نے فرمایا:
لَا یُـقْدِسَ اللّٰہؑ اُمَّـۃً قَادَتْـھُمْ اِمْـرَاَۃ۔ (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۱۰)
’’اللہ تعالیٰ اس قوم کو پاکیزگی عطا نہیں فرماتے جس کی قیادت عورت کر رہی ہو۔‘‘
(5) امام طبرانیؒ حضرت جابر بن سمرۃؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرمؐ نے فرمایا:
لَنْ یُّـفْلِحَ قَوْم یَمْلِکُ رَاْبَـھُمْ اِمْرَاَۃ۔ (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۰۹)
’’وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جن کی رائے کی مالک عورت ہو۔‘‘
(6) امام ابوداؤد طیاسیؒ حضرت ابوبکرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآبؐ نے فرمایا:
لَنْ یُّـفْلِحَ قَوْم اَسْنَدُوْا اَمْرَھُمْ اِلٰی اِمْرَاَۃٍ۔ (طیاسی ص ۱۱۸)
’’وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنی حکمرانی عورت کے حوالہ کر دی۔‘‘
(7) امام ابن الاثیرؒ اس روایت کو ان الفاظ سے نقل کرتے ہیں:
مَا اَفْلَحَ قَوْم قَیِّمُھُمْ اِمْرَاَۃ۔ (النہایۃ ج ۴ ص ۱۳۵)
’’وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جس کی منتظم عورت ہو۔‘‘
(8) مسند احمد میں ہے:
لَنْ یُّـفْلِحَ قَوْم تَمْلِکُھُمْ اِمْرَاَۃ۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۴۳)
’’وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس کی حکمران عورت ہو۔‘‘
(9) اہل تشیع کی معروف کتاب ’’مستدرک الرسائل‘‘ میں، جو الحاج مرزا حسین نوری طبرسی کی لکھی ہوئی ہے اور قم سے طبع ہوئی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو حضرت حوا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں ناقص العقل والدین بنایا ہے اور
لَمْ اَجْعَلْ مِنْکُنَّ حَاکِمًا وَّلَمْ ابْعَث مِنْکُـنَّ نَبِـیـًّا۔ (مستدرک الرسائل باب ان المراۃ لا تولی القضاء)
’’میں نے تم عورتوں میں سے کوئی حاکم نہیں بنایا اور نہ تم میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔‘‘
یہاں حاکم نہیں بنایا کا معنیٰ یہ ہوگا کہ حاکم بننے کی اجازت نہیں دی، اس لیے جو عورتیں کسی دور میں حاکم بن گئی ہیں ان کی حیثیت وہی ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورتوں کی ہے۔
(10) اسی مستدرک الرسائل میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلامؓ نے جناب رسول اللہؐ سے کچھ سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال حضرت آدمؑ کی پسلی سے حضرت حواؑ کو پیدا کرنے کے بارے میں بھی تھا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت حواؑ کو حضرت آدمؑ کے پورے وجود سے پیدا کیا گیا یا وجود کے کچھ حصہ سے بنایا گیا تو جناب سرور کائناتؐ نے فرمایا کہ
بَلْ مِنْ بَعْضِہ وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ کُلِّہ لَجَازَ الْقَضَاءُ فِی النِّسَآءِ کَمَا یَجُوْزُ فِی الرِّجَالِ۔
’’بلکہ حضرت حواؓ کو حضرت آدمؑ کے وجود کے بعض حصہ سے پیدا کیا گیا اور اگر انہیں پورے وجود سے پیدا کیا جاتا تو قضا کا منصب عورتوں کے لیے بھی اسی طرح جائز ہو جاتا جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے۔‘‘
(11) اہل تشیع کے ہی ایک اور محقق الاستاذ الشیخ جعفر السبحانی اپنی کتاب ’’معالم الحکومۃ الاسلامیہ‘‘ میں، جو مکتبہ الامام امیر المومنین العامۃ اصفہان سے چھپی ہے، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرمؐ نے عورتوں کے بارے میں احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
وَلَا تَـوَلَّی الْقَضَآءِ۔ (المیزان ج ۱۸ ص ۹۳۔ معالم الحکومۃ الاسلامیہ ص ۲۷۷)
’’عورت قضا کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔‘‘
جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح ارشادات کے بعد اس امر میں اب شک و شبہ کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ شرعاً کسی عورت کے حکمران بننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
(۳) اجماع امت
قرآن و سنت کے بعد دلائل شرعیہ میں اجماع کا درجہ ہے اور چودہ سو سال سے امت مسلمہ کا اس پر اجماع و اتفاق چلا آتا ہے کہ عورت شرعاً حکمران نہیں بن سکتی۔
(1) خلفاء راشدین کے مبارک دور سے آج تک امت مسلمہ کا اجماعی تعامل اس امر پر ہے کہ کوئی عورت کسی خطہ میں مسلمانوں کی حکمران نہیں بنی۔ اس لیے ہمارے نزدیک امت کا یہ عمل صرف اجماع نہیں بلکہ ’’تواتر عملی‘‘ کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ عورت کو حکمران نہ بنانے کا یہ عمل اس قدر مسلسل اور متواتر ہے کہ چودہ سو سالہ تاریخ میں کہیں بھی اس کی قابل توجہ خلاف ورزی نظر نہیں آتی۔ بلکہ کسی موقع پر اگر جزوی طور پر اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے اس پر گرفت کی ہے جیسا کہ نویں صدی ہجری کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ مصر میں بنی ایوب خاندان کی ایک خاتون ’’شجرۃ الدر‘‘ حکمران بن گئی۔ اس وقت بغداد میں خلیفہ ابوجعفر مستنصر باللہؒ کی حکومت تھی، انہوں نے یہ واقعہ معلوم ہونے پر امراء کے نام تحریری پیغام بھیجا کہ
اعلمونا ان کان ما بقی عند کم فی مصر من الرجال من یصلح للسلطنۃ فنحن نرسل لکم من یصلح لھا اما سمعتم فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا افلح قوم ولوا امرھم امراۃ۔ (اعلام السناء ج ۲ ص ۲۸۶)
’’ہمیں بتاؤ اگر تمہارے پاس مصر میں حکمرانی کے اہل مرد باقی نہیں رہے تو ہم یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا۔‘‘
خلیفہ وقت کے اس پیغام پر ’’شجرۃ الدر‘‘ منصب سے معزول ہوگئی اور اس کی جگہ سپہ سالار کو مصر کا حکمران بنا لیا گیا۔
(2) امام بغویؒ (شرح السنۃ ج ۷۷) میں فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی۔
(3) امام ابوبکر بن العربیؒ (احکام القرآن ج ۳ ص ۴۴۵) حضرت ابوبکرؓ والی حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں:
وھذا نص فی الامراۃ لا تکون خلیفۃ ولا خلاف فیہ۔
’’یہ حدیث اس بارے میں نص ہے کہ عورت خلیفہ نہیں بن سکتی اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔‘‘
(4) امام ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں:
اجمع المسلمون علیہ۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ ص ۱۴۹)
’’مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔‘‘
(5) امام الحرمین الجوینیؒ فرماتے ہیں:
واجمعوا ان المراۃ لایجوز ان تکونا اماما۔ (الارشاد فی اصول الاعتقاد ص ۲۵۹)
’’اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کا حکمران بننا جائز نہیں۔‘‘
(6) حافظ ابن حزمؒ امت کے اجماعی مسائل کے بارے میں اپنی معروف کتاب ’’مراتب الاجماع‘‘ میں فرماتے ہیں:
واتفقوا ان الامامۃ لا تجوز لامراۃ۔ (مراتب الاجماع ص ۱۲۶)
’’اور علماء کا اتفاق ہے کہ حکمرانی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔‘‘
(7) دورِ حاضر کے معروف محقق ڈاکٹر منیر عجلانی لکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی عالم کو نہیں جانتے جس نے عورت کی حکمرانی کو جائز کہا ہو۔
فالاجماع فی ھذہ القضیۃ تام لم یشذ عنہ۔ (عبقریۃ الاسلام فی اصول الحکم ص ۷۰)
’’اس مسئلہ میں اجتماع اتنا مکمل ہے کہ اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔‘‘
(8) پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے ۱۹۵۱ء میں ۲۲ دستوری نکات پر اتفاق کیا اور ان میں حکومت کے سربراہ کے لیے مرد کی شرط کو لازمی قرار دیا۔
(۴) اجتہاد و قیاس
دلائل شرعیہ میں چوتھا درجہ اجتہاد اور قیاس کا ہے۔ اجتہاد اور قیاس کا اصل محل اگرچہ غیرمنصوص مسائل ہیں کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مسائل میں اجتہاد کی اجازت دی ہے جن میں قرآن و سنت کی واضح ہدایات موجود نہ ہوں۔ لیکن چونکہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح اور ان سے احکام و مسائل کا استنباط بھی اجتہاد اور قیاس سے تعلق رکھنے والے امور ہیں اس لیے شاید کسی ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ ممکن ہے فقہائے اسلام اور مجتہدین نے احکام و مسائل کے استنباط میں عورت کی حکمرانی کے لیے کوئی گنجائش کسی درجہ میں دیکھ لی ہو۔ لیکن یہ شبہ بھی وہم و تخیل سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ امت کے تمام مسلمہ فقہی مکاتب فکر کے مجتہدین نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ حکمرانی کے منصب کے لیے دیگر شرائط کے علاوہ مرد ہونا بھی ضروری ہے اور عورت کے حکمران بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
فقہ حنفی
فقہ حنفی کی معروف و مستند کتاب ’’الدر المختار‘‘ اور اس کی شرح ’’رد المحتار‘‘ میں اس امر کی تصریح ہے کہ حکمران کے لیے دوسری شرائط کے ساتھ مرد ہونا بھی ضروری ہے اور
لا یصح تقریر المراۃ فی وظیفۃ الامامۃ۔ (شامی ج ۴ ص ۳۹۵، ج ۱ ص ۵۱۲)
’’عورت کو حکمرانی کے کام پر مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔‘‘
فقہ شافعی
فقہ شافعیؒ کی مستند کتاب ’’المجموع شرح المہذب‘‘ میں لکھا ہے:
القضاء لایجوز لامراۃ۔
’’قضا کا منصب عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔‘‘
فقہ حنبلی
فقہ حنبلیؒ کی مستند کتاب المغنی (ج ۱۱ ص ۳۸۰) میں ہے:
المراۃ لا تصلح للامامۃ ولا لتولیۃ البلد ان ولھذا لم یول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا احد من خلفاء ولا من بعدھم قضاء ولا ولایۃ ولو جاز ذلک لم تخل منہ جمیع الزمان غالباً۔
’’عورت نہ ملک کی حاکم بن سکتی ہے اور نہ شہروں کی حاکم بن سکتی ہے۔ اسی لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو مقرر نہیں کیا، نہ ان کے خلفاء نے کسی کو مقرر کیا اور نہ ہی ان کے بعد والوں نے قضا یا حکمرانی کے کسی منصب پر کسی عورت کو فائز کیا اور اگر اس کا کوئی جواز ہوتا تو یہ سارا زمانہ اس سے خالی نہ ہوتا۔‘‘
فقہ مالکی
فقہ مالکیؒ کی مستند کتاب ’’منحۃ الجلیل‘‘ میں نماز کی امامت، لوگوں کے درمیان فیصلوں، اسلام کی حفاظت، حدود شرعیہ کے نفاذ اور جہاد جیسے احکام کی بجا آوری کے لیے شرائط بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:
فیشترط فیہ العدالہ والذکورۃ والفطنۃ والعلم۔
’’پس اس کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو، مرد ہو، سمجھدار ہو اور عالم ہو۔‘‘
فقہ ظاہری
اہل ظاہر کے معروف امام حافظ ابن حزمؒ فرماتے ہیں:
ولا خلاف بین واحد فی انھا لاتجوز لامراۃ۔ (المحلی ج ۹ ص ۳۶۰۔ الملل ج ۴ ص ۱۶۷)
’’اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حکمرانی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔‘‘
اہل تشیع
معروف شیعہ محقق الاستاذ الشیخ جعفر السبحانی لکھتے ہیں:
فقد اجمع علماء الامامیۃ کلھم علی عدم انعقاد القضاء للمراۃ وان استکملت جمیع الشرائط الاخریٰ۔ (معالم الحکومۃ الاسلامیۃ ص ۲۷۸)
’’امامیہ مکتب فکر کے تمام علماء کا اس امر پر اجماع ہے کہ قضاء کا منصب عورت کے سپرد کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ اس میں دوسری تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔‘‘
اہل حدیث
معروف اہلحدیث عالم قاضی شوکانیؒ حضرت ابوبکرؓ والی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
فیہ دلیل علی ان المراۃ لیست من اھل الولایات ولایحل لقوم تولیتھا۔ (نیل الاوطار ج ۸ ص ۲۷۴)
’’اس میں دلیل ہے کہ عورت حکمرانی کے امور کی اہل نہیں ہے اور کسی قوم کے لیے اس کو حکمران بنانا جائز نہیں ہے۔‘‘
جامعہ ازہر
عالمِ اسلام کے قدیم علمی مرکز جامعہ ازہر قاہرہ کے سربراہ معالی الدکتور الشیخ جاد الحق علی جاد الحق اور دیگر علماء ازہر کا متفقہ فتوٰی کویت کے معروف جریدہ ’’المجتمع‘‘ نے گزشتہ سال نومبر میں شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عورت کو حکمران بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔
دارالعلوم دیوبند
ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ماہنامہ ’’دارالعلوم‘‘ نے نومبر ۱۹۸۹ء کے شمارہ میں مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی حبیب الرحمٰن خیرآبادی کا مفصل فتوٰی شائع کیا ہے جس میں دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ عورت کو حکمران بنانے کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔
الشیخ بن باز
سعودی عرب کے مفتی اعظم معالی الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ الباز کا فتوٰی ہفت روزہ ’’تنظیم اہل حدیث‘‘ لاہور کے ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۹ء کے شمارہ میں شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ
ان الاحکام الشرعیۃ العامۃ تتعارض مع تولیۃ النسآء الولایات العامۃ۔
’’شریعت کے عام احکام عورتوں کو حکمرانی کے معاملات سپرد کرنے کی نفی کرتے ہیں۔‘‘
الغرض عورت کی حکمرانی کے بارے میں علماء کا موقف قرآن و سنت اور اجماعِ امت کی روشنی میں اس قدر واضح اور مبرہن ہو کر سامنے آ چکا ہے کہ اب اس میں مزید کلام کی گنجائش نظر نہیں آتی اور نہ ہی اہلِ علم و دانش اور اصحابِ فہم و فراست کے لیے اس مسئلہ میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی رہ گیا ہے کہ قرآن و سنت کے صریح احکام اور امتِ مسلمہ کے چودہ سو سالہ تواتر عملی کی رو سے کسی مسلم ریاست میں خاتون کے حکمران بننے کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ البتہ اس موقف اور اس کے مطابق علماء کرام کی اجتماعی جدوجہد کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات اور اعتراضات سامنے آ رہے ہیں جن کا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جائزہ لینا ہے۔
ملکہ سبا
یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں ملکہ سبا حضرت بلقیس رضی اللہ عنہا کا ذکر موجود ہے جو سبا کی حکمران تھیں اور جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اگر عورت کی حکمرانی ناجائز ہوتی تو ان کا ملکہ کی حیثیت سے قرآن کریم میں ذکر نہ ہوتا۔ لیکن جب ہم اس واقعہ کے حوالہ سے قرآن کریم کے ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اعتراض بے وزن نظر آتا ہے اس لیے کہ
- قرآن کریم نے ملکہ سبا کی حکومت کا جس دور کے حوالہ سے ذکر کیا ہے وہ ان کا کفر کا دور ہے اور قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وہ اس دور میں سورج کی پجاری تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے بعد ملکہ سبا کی حکومت کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔
- حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ جو خط ملکہ سبا کو ارسال کیا تھا اس میں اسے مسلمان ہونے کی دعوت ان الفاظ میں دی تھی کہ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَیّ وَاْتُوْنِیْ مُسْلِمِیْن (النمل) ’’مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس چلے آؤ‘‘۔ یہ دعوت ملکہ سبا اور اس کی قوم کو تھی اور اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ملکہ سبا ایمان لائی تھیں۔ اس لیے سرکشی نہ کرنے اور مطیع ہو کر چلے آنے کا مفہوم یہی تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی الگ اور مستقل حکومت باقی نہیں رہی تھی۔
- اگر بالفرض اسلام قبول کرنے کے بعد ملکہ سبا کی حکومت باقی رہی ہو تو بھی ان کا یہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے جو احکام اور واقعات قرآن میں مذکور ہوئے ہیں اور قرآن کریم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف حکم دیا ہے تو وہ احکام باقی نہیں رہے بلکہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصولِ فقہ کی معروف کتاب ’’نور الانوار‘‘ میں صراحت کی ہے اور اسی بنیاد پر معروف مفسر قرآن علامہ آلوسیؒ نے ملکہ سبا کی حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ’’اس سے عورت کی حکمرانی کے جواز میں استدلال کرنا درست نہیں‘‘۔ (روح المعانی ج ۱۹ ص ۱۸۹)
ام المؤمنین حضرت عائشہؓ
یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر عورت کی حکمرانی جائز نہ ہوتی تو ام المؤمنین حضرت عائشہؓ جنگِ جمل میں صحابہ کرامؓ کے ایک گروہ کی قیادت کیوں کرتیں؟ مگر یہ اعتراض بھی غلط اور بے بنیاد ہے اس لیے کہ
- ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امارت اور حکمرانی کا کوئی دعوٰی نہیں کیا تھا اور نہ اس کے لیے جنگ لڑی تھی بلکہ وہ صرف حضرت عثمانؓ کے خون کے بدلہ کا مطالبہ لے کر میدان میں آئی تھیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔
- حضرت عائشہؓ کا یہ عمل ان کی اجتہادی خطا تھی جس پر خود ام المومنینؓ نے کئی بار پشیمانی کا اظہار فرمایا، مثلاً ’’طبقات ابن سعد‘‘ ج ۸ ص ۸۱ میں ہے کہ ام المومنینؓ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ ’’وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِکُم‘‘ کی تلاوت کرتیں تو روتے روتے ان کا آنچل آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اس آیت کریمہ میں ازواج مطہراتؓ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہیں۔ اسی طرح امام مالکؒ (مستدرک ج ۴ ص ۸) میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی کہ انہیں وفات کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضۂ اطہر میں دفن نہ کیا جائے کیونکہ ان سے حضور علیہ السلام کے بعد ایک غلطی سرزد ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں ’’مصنف ابن ابی شیبہ‘‘ ج ۱۵ ص ۲۷۷ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول منقول ہے کہ ’’اے کاش! میرے دس بیٹے مر جاتے لیکن میں یہ سفر نہ کرتی‘‘۔ اس لیے حضرت ام المومنین کے اس عمل کو دلیل بنانا درست نہیں ہے۔
فقہائے احناف
یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ فقہائے احناف عورت کو قاضی بنانے کے حق میں ہیں اس لیے عورت قاضی بن سکتی ہے تو حاکم کیوں نہیں بن سکتی؟ لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہے اور اس سلسلہ میں فقہائے احناف کے موقف کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ فتوٰی علی الاطلاق فقہائے احناف نے نہیں دیا کہ عورت کو قاضی بنایا جا سکتا ہے بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی حاکم نے عورت کو قاضی بنا دیا ہے اور اس عورت نے قاضی کی حیثیت سے فیصلے کیے ہیں تو اس کے فیصلے ان مقدمات میں نافذ ہوں گے جن کا تعلق حدود و قصاص سے نہیں ہے، اور حدود و قصاص کے مقدمات میں اس کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ علامہ شامیؒ ’’رد المحتار‘‘ ج ۴ ص ۲۹۵ میں صراحت کرتے ہیں کہ غیر حدود و قصاص میں عورت کی قضا نافذ ہو گی لیکن اس کو قاضی بنانے والا گنہگار ہو گا۔ اس لیے فقہائے احناف کے موقف کی عملی صورت یوں بنتی ہے کہ
- حدود و قصاص کے مقدمات میں عورت قاضی نہیں بن سکتی اور نہ ہی اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔
- باقی ماندہ مقدمات میں بھی عورت کو قاضی بنانے والا گنہگار ہو گا لیکن اس کے فیصلے نافذ ہو جائیں گے۔
اس لیے فقہائے احناف کے اس موقف کو عورت کی حکمرانی کے جواز کے لیے دلیل بنانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
امام ابن جریر طبریؒ
مشہور مفسر قرآن امام ابن جریر طبریؒ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عورت کو قاضی بنانے کے جواز کا فتوٰی دیا تھا لیکن علامہ آلوسیؒ نے اس کی تردید کرتے ہیں اور ’’روح المعانی‘‘ ج ۱۹ ص ۱۸۹ میں فرماتے ہیں کہ امام ابن جریرؒ کی طرف سے اس فتوٰی کی نسبت درست نہیں ہے۔
حضرت تھانویؒ
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتوٰی بڑے شدومد کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جو ’’امداد الفتاوٰی‘‘ میں موجود ہے اور جس میں بھوپال کی بیگمات کی نسبت کے حوالہ سے یہ فتوٰی دیا گیا ہے کہ عورت کو حکمران بنانا جائز ہے۔ لیکن اس فتوٰی کا سہارا لینا بھی بے سود ہے اس لیے کہ حضرت تھانویؒ نے اس فتوٰی سے رجوع کر لیا تھا جس کا ثبوت یہ ہے کہ
- اس فتوٰی میں ملکہ سبا کی حکومت کو استدلال کی بنیاد بنایا گیا ہے مگر حضرت تھانویؒ نے خود اپنی تفسیر ’’بیان القرآن‘‘ میں اس استدلال کو رد کر دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے۔ (بیان القرآن ج ۸ ص ۸۵)
- حضرت تھانویؒ نے آخری عمر میں ’’احکام القرآن‘‘ خود اپنی نگرانی میں تحریر کرائی جس کا سورۃ النمل والا حصہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے لکھا جو حضرت تھانویؒ کو پڑھ کر سنایا گیا اور ان کی منظوری سے شائع ہوا۔ اس میں دلائل کے ساتھ اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ عورت شرعاً حکمران نہیں بن سکتی۔
عورت اور پارلیمنٹ
یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ خواتین کو پارلیمنٹ کی رکنیت دینے کے مسئلہ پر علماء نے مخالفت نہیں کی بلکہ خود علماء کی طرف سے بعض خواتین کو اسمبلیوں کا رکن بنوایا گیا، اس لیے جب عورت اسمبلی کی ممبر بن سکتی ہے تو اسی اسمبلی میں قائد ایوان کیوں نہیں بن سکتی؟ مگر یہ سوال بھی لاعلمی پر مبنی ہے کیونکہ اسمبلی کی رکنیت اور چیز ہے اور حکمرانی کے اختیارات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدینؓ نے خواتین کو مشاورت میں شریک کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ خود بھی متعلقہ امور میں عورتوں سے مشاورت کرتے رہے ہیں۔ اس لیے علمی اور عوامی دونوں امور میں عورت کو اسمبلی کی رکن کی حیثیت سے مشاورت میں شریک کیا جا سکتا ہے البتہ اس کے لیے پردہ کے شرعی احکام کی پابندی ضروری ہو گی مگر حکمرانی کے اختیارات عورت کے حوالے کرنے سے قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔
سربراہِ مملکت یا سربراہِ حکومت
یہ الجھن بھی پیش کی جا رہی ہے کہ قرآن و سنت میں عورت کو سربراہ مملکت بنانے کی ممانعت کی گئی ہے اور سربراہِ مملکت تو صدر ہوتا ہے جبکہ وزیراعظم سربراہِ حکومت ہوتا ہے، اس لیے اس ممانعت کا اطلاق صرف صدر پر ہوتا ہے وزیراعظم پر نہیں ہوتا۔ لیکن تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ یہ الجھن بھی ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ
- ابتدائے اسلام میں مملکت اور حکومت کی تقسیم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، سربراہِ مملکت اور سربراہِ حکومت کے عہدے ایک ہی شخصیت کے پاس ہوتے تھے اس لیے قرآن و سنت نے عورت کے حاکم ہونے کی جو ممانعت کی ہے وہ دونوں حیثیتوں کو شامل ہے، اور اگر ان دونوں حیثیتوں کو الگ الگ کر لیا جائے تو اس ممانعت کا اطلاق ہر ایک پر ہو گا۔ اس لیے اس اصول کے مطابق عورت نہ سربراہ مملکت بن سکتی ہے اور نہ ہی سربراہ حکومت کا منصب سنبھال سکتی ہے۔
- سربراہِ مملکت اور سربراہِ حکومت کی منصبی حیثیتوں کو الگ الگ کر کے بھی تجزیہ کیا جائے تو ممانعت کا پہلا مصداق سربراہِ حکومت کا منصب قرار پاتا ہے کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو اس ضمن میں محدثین نے روایت کیے ہیں ان میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو گی جس نے اپنے امر کا والی عورت کو بنا دیا۔ یا یہ فرمایا کہ جب تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہوں گے تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہو گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ’’امر‘‘ اور ’’امور‘‘ کا تعلق مملکت اور حکومت میں سے کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ امور کا طے کرنا تو حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ان احادیث کی روشنی میں عورت کے لیے حکمرانی کی ممانعت کا مصداق سب سے پہلے سربراہِ حکومت ہے اور کسی عورت کے وزیراعظم بننے کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے۔
جمہوری عمل اور علماء
یہ اعتراض بھی سامنے لایا گیا ہے کہ پاکستان میں خاتون کا وزیراعظم کے منصب پر فائز ہونا جمہوری عمل کا نتیجہ ہے اور یہ وہی جمہوری عمل ہے جس میں خود علماء کی جماعتیں حصہ لیتی رہی ہیں اور اب بھی اس میں شریک ہیں، اس لیے جب علماء اس جمہوری عمل کو تسلیم کرتے ہیں اور خود اس میں حصہ لیتے ہیں تو اس کے نتائج کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ علماء نے کسی دور میں بھی آزاد جمہوری عمل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اب وہ اسے قبول کرتے ہیں، بلکہ علماء نے جدوجہد کر کے
- ’’قراردادِ مقاصد‘‘ کی صورت میں جمہوری عمل کو قرآن و سنت کا پابند قرار دلوایا۔
- ۲۲ دستوری نکات کی صورت میں اسلامی اصولوں کے پابند جمہوری عمل کا تصور پیش کیا۔
- ۱۹۷۳ء کے دستور میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دینے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنائے جانے کی ضمانت کی دفعات شامل کرائیں۔
اس لیے جب علماء قیامِ پاکستان سے اب تک آزاد جمہوری عمل کو رد کرتے ہوئے قرآن و سنت کے دائرہ میں محدود جمہوری عمل کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں تو انہیں جمہوری عمل کے ہر اس فیصلے کو مسترد کرنے کا حق حاصل ہے جو قرآن و سنت کے احکام کے منافی ہو۔
دستور کی خلاف ورزی
بعض ذمہ دار حضرات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عورت کی حکمرانی کی مخالفت ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس پر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان حضرات کا یہ کہنا مغالطہ پر مبنی ہے بلکہ اگر دستوری دفعات کا تجزیہ لیا جائے تو خود عورت کو حکمران بنانا آئین کی خلاف ورزی قرار پاتا ہے کیونکہ دستور میں کسی عورت کو صدر یا وزیراعظم بنائے جانے کا جواز صریحاً مذکور نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ دستور اس بارے میں خاموش ہے۔ لیکن جب سے ’’قراردادِ مقاصد‘‘ کو دستور کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا ہے آئینی طور پر اس بات کی پابندی ضروری ہو گئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ یا حکم نافذ نہ کیا جائے۔ اس لیے جب عورت کو حکمران بنانا قرآن و سنت کی رو سے جائز نہیں ہے تو قراردادِ مقاصد کی روشنی میں خودبخود یہ پابندی ضروری ہو جاتی ہے کہ کسی عورت کو وزیراعظم نہ بنایا جائے۔ اس بنا پر عورت کی حکمرانی کی مخالفت آئین کی خلاف ورزی نہیں بلکہ عورت کو وزیراعظم بنانا ملک کے دستور کی خلاف ورزی قرار پاتا ہے۔
اس ضمن میں ایک اور نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ ۱۹۷۳ء کے دستور کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مولانا مفتی محمودؒ، مولانا شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء نے اس دستور پر دستخط کر دیے تھے تو انہوں نے اسے اسلامی تسلیم کر لیا تھا اس لیے اس دستور کے مطابق جو کام ہو گا وہ اسلام کے مطابق ہی ہو گا۔ لیکن یہ سراسر مغالطہ ہے کیونکہ ۱۹۷۳ء کا دستور تیار کرنے والی دستور ساز اسمبلی میں جو ارکان تھے انہوں نے اس دستور پر غیر مشروط دستخط نہیں کیے تھے بلکہ طویل مذاکرات کے نتیجہ میں یہ آئینی ضمانت حاصل کی گئی تھی کہ ملک میں تمام قوانین کو سات سال کے اندر قرآن و سنت کے مطابق تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ ضمانت خود اسی آئین میں درج ہے اور اس ضمانت کے حصول کے بعد علماء نے آئین پر دستخط کیے تھے۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ علماء ملک کے آئین و قانون کو اس طرح غیر مشروط ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انہیں قرآن و سنت پر بالادستی حاصل ہو جائے بلکہ بالادستی قرآن و سنت کی ہے اور علماء کی تمام تر جدوجہد کا مرکزی ہدف یہی ہے کہ آئین و قانون کو قرآن و سنت کی بالادستی کا عملاً پابند بنایا جائے۔
محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت
یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ جو علماء آج عورت کے حکمران بننے پر مخالفت کر رہے ہیں ان کی اکثریت نے ۱۹۶۴ء کے صدارتی انتخابات میں محترم فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی۔ لیکن یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے کیونکہ اس وقت علماء کی تین بڑی جماعتیں تھیں۔ (۱) جمعیۃ علماء اسلام پاکستان جس کی قیادت مولانا عبد اللہ درخواستی، مولانا مفتی محمودؒ اور مولانا غلام غوث ہزارویؒ کر رہے تھے۔ جمعیۃ اہل حدیث پاکستان جس کی قیادت مولانا محمد اسماعیل سلفیؒ کے ہاتھ میں تھی۔ (۳) اور جمعیۃ العلماء پاکستان جس کے سربراہ صاحبزادہ سید فیض الحسنؒ تھے۔ ان تینوں جماعتوں نے باقاعدہ جماعتی فیصلوں کی صورت میں اعلان کیا تھا کہ چونکہ عورت کو ملک کا حکمران بنانا شرعاً جائز نہیں ہے اس لیے وہ محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت سے قاصر ہیں۔
علماء پہلے کہاں تھے؟
یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ علماء کو اچانک یہ بات سوجھی ہے کہ عورت کو وزیر بنانا درست نہیں ہے، اس سے قبل علماء خاموش رہے ہیں، ان کے سامنے دستور بنے ہیں اور ساری باتیں ہوتی رہی ہیں مگر علماء نے کبھی اس قسم کی مہم نہیں چلائی۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ یہ بھی محض مفروضہ ہے جو حالات اور واقعات کے تسلسل سے بے خبری کے باعث قائم کر لیا گیا ہے ورنہ
- جب قراردادِ مقاصد میں یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ کوئی کام قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو گا تو اس مسئلہ میں بھی علماء کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی تھی۔
- اس کے باوجود تمام مکاتب فکر کے ۳۱ سرکردہ علماء نے ۱۹۵۲ء کے طے کردہ ۲۲ متفقہ دستوری نکات میں یہ طے کر دیا تھا کہ سربراہِ حکومت کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔
- ۱۹۷۳ء کا دستور جب دستور ساز اسمبلی میں زیربحث آیا تو شیخ الحدیث مولانا عبد الحقؒ (اکوڑہ خٹک) نے اس مسئلہ پر مستقل دستوری ترمیم پیش کی تھی جو دستور ساز اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس پر مولانا مرحوم نے اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران دلائل کے ساتھ اس مسئلہ کو واضح کیا تھا کہ عورت کو حکمران بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔
- جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں وفاقی مجلس شورٰی نے آئینی ترامیم کے لیے محترم فدا محمد خان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تھی، اس کمیٹی کے رکن مولانا قاضی عبد اللطیف نے عورت کی حکمرانی کے مسئلہ کی وضاحت کی اور باقی ارکان کے نہ ماننے کی وجہ سے اپنا اختلافی نوٹ تحریر کرایا جو کمیٹی کے ریکارڈ میں موجود ہے۔
- حالیہ انتخابات کے بعد جب ایک خاتون کے وزیراعظم بننے کے امکانات واضح ہونے لگے تو جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا سمیع الحق نے صدر جناب غلام اسحاق خان سے ملاقات کر کے ان پر مسئلہ کی شرعی پوزیشن واضح کی اور پورے ملک کے علماء کی طرف سے اتمام حجت کا فریضہ ادا کیا۔ اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ علماء اس سے قبل خاموش رہے ہیں اور اب ایک خاص پارٹی کی ضد میں اس کی وزیراعظم کی مخالفت کر رہے ہیں۔
قوتِ فیصلہ پارلیمنٹ کے پاس ہے
یہ بات بھی بعض حلقے پیش کر رہے ہیں کہ جمہوری نظام میں قوتِ فیصلہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے اور وزیراعظم صرف ان فیصلوں کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے وزیراعظم پر اس مطلق حکمرانی کا اطلاق نہیں ہوتا جس کی نفی قرآن و سنت میں عورت کے لیے کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات بھی اصول کے خلاف ہے اس لیے کہ
- اکثر جمہوری ممالک بالخصوص ترقی پذیر ممالک میں جمہوریت کی ہیئت کذائیہ یہ ہے کہ اکثریتی پارٹی پارلیمنٹ میں فیصلوں کا محور ہوتی ہے اور اکثریتی پارٹی کے فیصلوں کا محور اس کا لیڈر ہوتا ہے، اس لیے عملاً فیصلوں کی باگ ڈور بھی وزیراعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
- معروف مسلمان مفکر علامہ الماوردیؒ نے ’’الاحکام السلطانیہ‘‘ ص ۲۵ میں صراحت کی ہے کہ صرف (طے شدہ فیصلوں کو) نافذ کرنے والی وزارت اگرچہ کمزور وزارت ہے اور اس کی شرائط کم ہیں لیکن عورت کے لیے یہ وزارت بھی جائز نہیں ہے۔
اسلام میں خواتین کی ذمہ داریاں اور حقوق
مولانا قاری محمد طیبؒ
بعد الحمد والصلٰوۃ۔
بزرگانِ محترم! قرآن شریف کی آل عمران کی تین آیتیں اس وقت میں نے تلاوت کیں۔ اس میں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت مریم علیہا السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں ملائکہ علیہم السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس جلسہ کے منعقد کرنے کی غرض و غایت چونکہ عورتوں کو خطاب ہے اس لیے میں نے اس آیت کو اختیار کیا۔
واقعہ یہ ہے کہ عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں بلکہ بعض امور میں مردوں سے عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں، اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اسی سے بچہ تربیت پاتا ہے، سب سے پہلے جو سیکھتا ہے ماں سے سیکھتا ہے، باپ کی تربیت کا زمانہ شعور کے بعد آتا ہے، لیکن ہوش سنبھالتے ہی بلکہ بے ہوشی کے زمانے میں بھی ماں ہی اس کی تربیت کرتی ہے۔ گویا اس کی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود علم، نیکی، تقوٰی اور صلاحیتوں سے بھری ہوئی ہے وہی اثر بچے میں آئے گا، اور اگر خدانخواستہ ماں کی گود ہی ان نعمتوں سے خالی ہے تو وہ بچہ بھی خالی رہ جائے گا۔
خشتِ اول چوں نہد معمار کج
کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ جب عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اخیر تک عمارت ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ شروع کی اینٹ اگر سیدھی رکھ دی جائے تو اخیر تک عمارت سیدھی چلتی ہے۔ جس چیز کا آغاز اور ابتداء درست ہو جائے تو اس کی انتہا بھی درست ہو جاتی ہے۔ اس واسطے عورتوں کا مردوں سے زیادہ حق ہے اور ہم اسی حق کو زیادہ پامال کر رہے ہیں۔ مرد تو ہر جگہ موجود ہیں اور عورتوں کو سنانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر عورتیں مردوں کے حکم سے آئی ہیں تو مردوں کا شکریہ، اور اگر ازخود آئی ہیں تو پھر ان کے دینی جذبہ کی داد دینی چاہیئے کہ ان کے اندر بھی ازخود ایک جوش و جذبہ ہے کہ دینی باتیں سیکھیں اور معلوم کریں۔ بہرحال سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ان کے اندر دین کی طلب ہے۔ اگر خود پیدا ہوئی تو وہ شکرئیے کی مستحق ہیں اور اگر طلب پیدا کی گئی ہے تو اس طلب کے پیدا کرنے والے بھی اور جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ بھی شکرئیے کی مستحق ہیں۔ اس واسطے میں نے کہا مردوں سے عورتوں کا حق زیادہ ہے اس لیے کہ زندگی کی ابتداء انہیں سے ہوتی ہے۔
عورتوں کی قوتِ عقل
اس وجہ سے بھی کہ بچوں کا قصہ بعد میں آتا ہے، خود خاوند بھی عورت سے متاثر ہوتا ہے۔ عورتیں جب کسی چیز کو منوانا چاہتی ہیں تو منوا کے رہتی ہیں۔ وہ ضد کریں، ہٹ دھرمی کریں یا کچھ کریں خاوند کو مجبور کر دیتی ہیں۔ اس میں ایک پہلو جہاں عورتوں کے لیے عمدہ نکلتا ہے وہاں ایک بات کمزوری کی بھی نکلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ما رایت من ناقصات عقل و دین اذھب للب الرجل الحازم من احدکن۔
(یعنی) یہ عورتیں ہیں تو ناقص العقل، ان کی عقل کم ہے، مگر بڑے بڑے کامل العقل مردوں کی عقلیں اچک کر لے جاتی ہیں، اچھے خاصے عقل مند بھی ان کے سامنے پاگل بن جاتے ہیں۔ جب وہ چاہتی ہیں کہ یہ ہو تو مرد ان کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں۔
ہمارے ہاں اور یہاں آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہو گا اس لیے کہ عورتوں کا مزاج سب جگہ ایک ہی ہے اور مردوں کی ذہنیت بھی ایک ہی ہے، البتہ تمدن کا فرق ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ میں جو اکثر رسمیں ہوتی ہیں وہ رسمیں تباہ کن ہوتی ہیں۔ وہ دولت اور دین کو بھی برباد کرتی ہیں۔ جب مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی! کیوں ان خرافات میں پڑے ہوئے ہو؟ تم سمجھ دار اور عقل مند آدمی ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ دولت اور دین بھی برباد ہو رہا ہے تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ جی عورتیں نہیں مانتیں کیا کریں۔ گویا عورتیں حکّام ہیں، وہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے اور یہ غلام و رعایا ہیں ان کا فرض ہے کہ اطاعت کریں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیں تو یہ ناقص العقل مگر اچھے بڑے عقل والوں کی عقلیں اچک کر لے جاتی ہیں اور انہیں بے وقوف بنا دیتی ہیں۔ تو جب عورت میں یہ قوت موجود ہے کہ عقل مند کو بھی بے وقوف بنا دیتی ہے اور اچھے بھلے مرد کو مجبور بنا دے، اگر وہ کسی اچھی چیز کے لیے مرد کو مجبور کرے گی تو مرد کیوں نہیں مجبور ہو گا؟
اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے یوں کہہ دے کہ جناب سیدھی بات ہے آپ کا حکم واجب الاطاعت ہے، آپ خدا کی طرف سے میرے مربّی سب کچھ ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے میں بھی آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ وہ جھک مارے گا ضرور پڑھے گا چاہے خدا کی نہ پڑھے بیوی کی ضرور پڑھے گا۔ جب عورتیں ضد کر کے دنیا کی بات منوا لیتی ہیں کوئی وجہ نہیں کہ دین کی بات نہ منوا لیں۔ عورتوں کی بدولت بہت سے خاندانوں کی اصلاح ہو گئی ہے، عورتوں نے ضد کی، مرد مجبور ہو گئے۔ ہمارے ہاں بعض خاندان ایسے تھے جو کچھ خرافات میں مبتلا تھے، اس واسطے کہ گھر میں دولت تھی، کہیں سینما کہیں تھیٹر وغیرہ، نماز کا تو کہیں سوال ہی نہیں، اتفاق سے عورت نہایت صالح اور دیندار گھرانے کی آگئی۔ چند دن اس نے صبر کیا، بعد میں اس نے کہا صاحب! یہ نبھاؤ بڑا مشکل ہے اس واسطے کہ رمضان آئے گا تو میں روزے سے رہوں گی اور تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے اور پکانے پر مجھے مجبور کرو گے، میں پکانے کے لیے مجبور نہیں ہوں جہاں چاہے پکواؤ اس گھر میں یہ نہیں ہو گا۔ اس واسطے کہ اس بد دینی میں تمہاری اعانت کر سکوں یہ خود گناہ کی بات ہے۔ یا تو اپنا بندوبست کرو یا پھر ان خرافات کو چھوڑ دو۔ آخر مرد مجبور ہوئے، نماز روزے کے پابند ہو گئے اور ان میں بہت سی اچھی خصلتیں پیدا ہو گئیں۔ اس لیے سب سے بڑا مربّی تو عورت ہے جو گھر کے اندر موجود ہے اس کی تربیت سے آدمی کام لے۔
اس لیے اپنی بہنوں سے یہ خطاب ہے کہ جب وہ ایسا دباؤ ڈال سکتی ہیں کہ مرد ان کے سامنے مجبور ہیں تو جہاں دنیا کے لیے زیور، کپڑے لانے کے لیے، برتن لانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے دباؤ ڈالتی ہیں، اگر دیندار گھر بنانے کے لیے دباؤ ڈالیں تو یقیناً وہ دیندار بنیں اور وہ اپنے خاوند کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اس لیے ان کے دل میں نیکی، تقوٰی اور بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیئے تاکہ خاوند پر بھی اس کا اثر پڑے۔ تو ایک عورت بچوں پر، خاوند پر اور کنبہ والوں پر بھی بہتر اثر ڈال سکتی ہے۔
عموماً سننے میں آیا ہے کہ خاندانوں میں جو جھگڑے اور تفریقیں پیدا ہوتی ہیں عورتوں کی بدولت پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو اتار چڑھاؤ کر کے بدظن بنا دیتی ہیں۔ دو حقیقی بھائیوں میں لڑائی پیدا کر دیتی ہیں حتٰی کہ خاندانوں میں نزاع اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر عورت نیک نہاد اور نیک طینت ہے تو بڑے بڑے جھگڑے ختم کرا دیتی ہے، خاندان مل جاتے ہیں۔ اور اپنی اس طاقت کو نیکی میں کیوں نہ خرچ کیا جائے برائی اور بدی میں کیوں خرچ کیا جائے؟ جب اللہ نے ایک طاقت دی ہے تو اس کو صحیح راستے پر خرچ کیا جائے۔
اس واسطے میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی، اس میں خصوصیت سے عورتوں ہی کے واقعات کا ذکر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ ترین بی بی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی اس آیت کے پڑھنے کی نوبت آئی کہ عورتوں کو یہ شکایت پیدا نہ ہو، جب خطاب کیا جاتا ہے مردوں ہی کو کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے مردوں ہی کو خطاب کیا۔ تاکہ یہ غلط فہمی ان کی رفع ہو جائے، جیسے مردوں کو خطاب کیا ہے عورتوں کو بھی کیا ہے، کہیں مرد و عورت دونوں کو ملا کر خطاب کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو دین کی ترقی مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے ہے، جیسے فرمایا:
اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِیْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِیْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِیْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآءِمِیْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِیْنَ فُرُوْجَھُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذَّاکِرِیْنَ اللہَ کَثِیْرًا وَالذَّاکِرٰتِ اَعَدَّ اللہُ لَھُمْ مَّغْفِرَۃً وَّاَجْرًا عَظِیْمًا (احزاب ع ۵ پ ۲۲)
’’مسلم مرد مسلم عورت، مومن مرد اور مومن عورت، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورت، سچا مرد اور سچی عورت، صدقہ دینے والا مرد اور صدقہ دینے والی عورت، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورت، حیا کا حفاظت کرنے والا مرد اور حیا کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورت، ان کے لیے وعدہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت، اجر عظیم اور آخرت کے درجات تیار کیے ہیں۔‘‘
اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راستہ پر چل کر جتنی ترقی مرد کر سکتا ہے وہی بعینہٖ عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایک مرد ولی کامل بن سکتا ہے تو عورت بھی ولی کامل بن سکتی ہے۔ اسلام میں جیسے مردوں میں اولیاء اللہ کی کمی نہیں ہے ویسے ہی عورتوں میں بھی اولیاء اللہ کی کمی نہیں ہے۔ اس بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ولایت کے مقام کو پہنچی ہیں اور ولیٔ کامل گزری ہیں۔ ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ کہیں حضرت رابعہ بصریہؒ، کہیں رابعہ عدویہؒ، اور پھر صحابیاتؓ جتنی ہیں وہ تو ساری اولیائے کاملین میں سے ہیں۔ تو تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں میں بڑی بڑی کامل عورتیں پیدا ہوئی ہیں۔ پھر ہر فن کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ محدث، مفسر، ادیب، شاعر اور مؤرخ بھی گزری ہیں۔ ان کی تصنیفات ہیں اور ہزاروں مرد ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر عورت دینی ترقی نہ کر سکتی تو یہ عورتیں کہاں سے پیدا ہو گئیں؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وحی کا آدھا علم میرے سارے صحابہؓ سے حاصل کرو اور آدھا علم تنہا عائشہؓ سے حاصل کرو۔ گویا عائشہ صدیقہؓ اتنی زبردست عالم ہیں۔ گویا نبوت کا آدھا علم صدیقہؓ کے پاس ہے، آدھا علم سارے صحابہؓ کے پاس ہے۔ صدیقہ عائشہؓ ایک عورت ہی تو ہے۔ تو عورت کو اللہ نے وہ رتبہ دیا کہ ہزارہا صحابہؓ ایک طرف اور ایک عورت ایک طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب عورت ترقی کرنے پر آتی ہے اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ بہت سے مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے چاہے دنیا میں ترقی کریں یا دین میں، علم و فضل میں بھی برابر چل سکتی ہیں۔
آپ نے امام ابی جعفر صادقؒ کا نام سنا ہو گا جن کی کتاب ’’طحاوی شریف‘‘ جو حدیث شریف کی کتاب ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عورت کا طفیل ہے۔ امام طحاویؒ کی بیٹی نے حدیث کی کتابیں املاء کی ہیں۔ باپ حدیث اور اس کے مطالب بیان کرتے تھے، بیٹی لکھتی جاتی تھی، اس طرح کتاب مرتب ہو گئی۔ گویا جتنے علماء اور محدث گزرے ہیں یہ سب امام ابی جعفر صادقؒ کی بیٹی کے شاگرد اور احسان مند ہیں۔ یہ بھی ایک عورت تو تھی۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ امام طحاویؒ کی بیٹی تو محدث بن سکے ہماری کوئی بہو بیٹی نہ بن سکے۔ وہی نسل ہے وہی چیز ہے وہی ایمان وہی دین ہے وہی علم آج بھی موجود ہے۔ توجہ اور بے توجہی کا فرق ہے۔ ان لوگوں نے توجہ دی تو عورتیں بھی ایسی بنیں کہ بڑے بڑے مرد بھی ان کے شاگرد بن گئے۔ آج توجہ نہیں کرتیں کمال نہیں پیدا ہوتا مگر صلاحیتیں موجود ہیں۔
عورت میں ترقی کی صلاحیت
بہرحال علماء اسلام نے ان بڑی بڑی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو ولایت کے مقام تک پہنچی اور کامل ہوئی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ عہدے اسلام نے ایسے رکھے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیے گئے۔ وہ اس بنا پر کہ عورت کا جو مقام ہے وہ حرمت و عزت کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں میں خلط ملط اور ملی جلی پھرے، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، برائیوں کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے عورتوں کو ایسے عہدے نہیں دیے گئے جس سے فتنوں کے دروازے کھلیں، لیکن صلاحیتیں موجود ہیں۔ صلاحیت اس حد تک تسلیم کی گئی ہے کہ علماء کی ایک جماعت اس بات کی بھی قائل ہے کہ عورت نبی بن سکتی ہے، رسول تو نہیں بن سکتی لیکن نبی بن سکتی ہے۔
نبی اسے کہتے ہیں جس سے ملائکہ علیہم السلام خطاب کریں اور خدا کی وحی اس کے اوپر آئے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو شریعت لے کر آئے اور خلق اللہ کی تربیت کرے۔ اس لیے تربیت کا مقام تو نہیں دیا گیا مگر ان کے نزدیک نبوت کا مقام عورت کے لیے ممکن ہے (۱)۔ حتٰی کہ ظاہریہ کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام نبی ہیں، فرشتے نے خطاب کیا ہے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کی والدہ نبی تھیں اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہا السلام جو ابتداء سے ہی مسلمان تھیں وہ نبوت کے مقام پر پہنچیں۔ تو نبوت سے بڑا عالم بشریت میں انسان کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدائی کمالات کے بعد اگر بزرگی کا کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا ہے اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں۔ جب عورت کو یہ درجہ بھی مل سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ عورت کی صلاحیت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ سب مقام طے کر سکتی ہے البتہ رسول نہیں بن سکتی۔ اس لیے محبتِ خداوندی کا مقام پیدا ہو، اس مقام کی عورتیں بھی گزری ہیں جن کے جذبات کا یہ عالم ہے۔
عورتوں نے بڑے بڑے اولیائے کاملین کی تربیت کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور صوفیاء کے امام ہیں اور سلسلۂ چشتیہ کے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہؓ ان کے مکان پر آئیں، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یا کوئی بات کرنی تھی۔ معلوم ہوا کہ حضرت حسن بصریؒ مکان پر نہیں ہیں، پوچھا کہاں گئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ دریا کے کنارے پر گئے ہیں اور ان کی عادت یہ ہے کہ اپنا ذکر اللہ یا عبادت وغیرہ دریا کے کنارے پر کرتے ہیں۔ بعض اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ذکر اللہ کے لیے جنگلوں کی راہ اختیار کی یا پہاڑوں میں بیٹھ کر اوراد کرتے ہیں، اس میں ذرا یکسوئی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دریا کے کنارے پر بیٹھنے کے بارے میں بھی صوفیاء لکھتے ہیں کہ قلب میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ مادی تاثیر اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ پانی کے کنارے پہنچ کر قلب میں فرحت زیادہ ہوتی ہے، جتنی فرحت اور نشاط پیدا ہو گا اتنا ہی قلب ذکر اللہ کی طرف مائل ہو گا۔ بنیادی اور باطنی وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ چلتا ہوا پانی خود اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ پانی کے ذکر کا اثر بھی انسان کے قلب پر پڑتا ہے تو اس کی طبیعت اور زیادہ ذکر اللہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ان وجوہ کی بنا پر حضرت حسن بصریؒ اکثر دریا کے کنارے پر جا کر عبادت کرتے تھے۔
بہرحال رابعہ بصریہؒ کو معلوم ہوا کہ حسن بصریؒ اپنی عادت کے مطابق ذکر و عبادت کرنے کے لیے دریا کنارے پر گئے ہیں، یہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ وہاں جا کے یہ عجیب ماجرا دیکھا کہ حسن بصریؒ نے پانی کے اوپر مصلّٰی بچھا رکھا ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہ مصلّٰی ڈوبتا ہے نہ تر ہوتا ہے گویا کرامت ظاہر ہوئی۔ رابعہ بصریہؓ کو یہ چیز ناگوار گزری اور اسے اچھا نہ سمجھا کیونکہ یہ عبدیت اور بندگی کی شان کے خلاف ہے۔ بندگی کے معنی یہ ہیں کہ بڑے سے بڑا بزرگ لوگوں میں ملا جلا رہے۔ کوئی امتیازی مقام پیدا کرنا یہ ایک قسم کا دعوٰی اور صورۃ تکبّر ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے جو میں کر سکتا ہوں۔ گویا میں بڑا صاحبِ کرامت اور صاحبِ تصرف ہوں۔ زبان سے اگرچہ نہ کہے مگر صورتحال سے ایک دعوٰی پیدا ہوتا ہے اور اہل اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز جو ہے وہ دعوٰی کرنا ہے اس لیے کہ اس میں تکبر اور کبر کی علامت ہے۔ اور ولایت کا مقام یہ ہے کہ تکبر مٹ کر خاکساری پیدا ہو، تو جس بزرگ میں تکبر یا کبر کی صورت بن جائے وہ بزرگ ہی کیا ہوا؟ حضرت رابعہؓ کو یہ چیز اس لیے ناگوار گزری کہ حسن بصریؒ بزرگوں کے امام اور وہ ایسی صورت پیدا کریں جس سے دعوٰی نکلتا ہو کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں گویا بڑا کرامت والا ہوں، حسن بصریؒ کے لیے یہ زیبا نہیں تھا، یہ شانِ عبدیت کے خلاف ہے۔ بلکہ درپردہ گویا یہ دعوٰی ہے کہ میں خدائی اختیارات رکھتا ہوں کہ تم اسباب کے تحت مجبور ہو کر پانی پر کشتی سے جاؤ اور میں مجبور نہیں ہوں میں پانی پر ویسے ہی چل سکتا ہوں میرے پاس خدائی قوتیں موجود ہیں۔ جب یہ دعوٰی ہو گیا تو بزرگی کہاں رہی؟ اس واسطے یہ چیز اچھی نہ معلوم ہوئی۔ مگر چونکہ یہ بھی بزرگ ہیں تو انہوں نے اصلاح کی۔ اصلاح کس طرح کی؟ زبان سے کچھ نہ کہا عمل سے اصلاح کی۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پانی کے اوپر مصلّٰی بچھا رکھا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مصلّٰی کو ہوا کے اوپر اڑا کر اس کے اوپر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب مصلّی ہوا کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہی ہیں، حسن بصریؒ سمجھ گئے کہ مجھے ہدایت کرنی مقصود ہے فورًا اپنا مصلّی لپیٹا اور دریا کے کنارے پر آگئے۔ رابعہ بصریہؒ نے بھی ہوا سے مصلّٰی لپیٹا اور نچے آئیں اور آ کر دو جملے ارشاد فرمائے، وہ کتنے قیمتی اور زریں جملے تھے کہ دین و دنیا کی ساری نصیحتیں ان دو جملوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ فرمایا اے حسن بصریؒ
بر آب روی خسے باشیٔ بر ہوا پری مگسے باشی
اے حسن بصریؒ! اگر تم پانی پر تیر گئے تو کوڑا کباڑ اور کچرا بھی پانی کے اوپر تیرتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور اگر رابعہ ہوا میں اڑی تو مکھیاں بھی تو ہوا میں اڑتی ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں کرو، اس پر کنٹرول حاصل کرو تاکہ صحیح معنٰی میں انسان بنو۔ انسان بننا کمال ہے مکھی بننا کمال نہیں ہے، آدمی بننا کمال ہے کوڑا کچرا بننا کمال نہیں ہے۔ اگر ہم ہوائی جہاز سے پچاس ہزار فٹ بلندی پر اڑ جائیں بے شک یہ بڑے کمال کی بات ہے مگر یہ حیوانیت کا کمال ہے انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ اگر ہم ڈبکتی کشتی کے ذریعے سمندر کی تہہ تک پہنچ جائیں یہ بھی حیوانیت کا کمال ہے اس لیے کہ مچھلیاں بھی تو پہنچتی ہیں۔ آدمی سے ہم اگر مچھلی بن گئے تو کونسا کمال کیا؟ اسی طرح ہوا میں کرگسیں بھی اڑتی ہیں، اگر آدمی سے کرگس بن گئے تو کونسا کمال کیا، یہ حیوانیت کا کمال ہے انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور عرش پہ باتیں کر رہا ہو، اپنے مصلّٰی کے اوپر ہو اور خدا سے اسے نیاز حاصل ہو، معاملات وہاں سے چل رہے ہوں۔ وہ فرشی ہو مگر حقیقت میں وہ عرشی ہو، فرش پر بیٹھے ہوئے عرش کے اوپر مقام ہو۔ یہ سب سے بڑا انسانیت کا کمال ہے جس کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے سکھلایا۔
تو رابعہ بصریہ نے کتنی قیمتی بات کہی کہ حضرت حسن بصریؒ نادم اور شرمندہ ہوئے اور توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں اسے بڑا کمال سمجھ رہا تھا مگر آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دیکھئے رابعہ بصریہ عورت ہے اور حسن بصریؒ مردوں کے امام ہیں۔ ایک عورت ایک مردِ کامل کو ہدایت کر رہی ہے اور اسے راستہ ہاتھ آجاتا ہے۔ اس لیے عورت اگر کمال پیدا کرنا چاہے تو وہ بڑے بڑے مردوں کی مربّی بن سکتی ہے۔
حضرت عائشہؓ، امت کی استاذ
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں لیکن حضرت عائشہ ؓ کے شاگرد ہیں، علم زیادہ تر انہی سے سیکھا ہے۔ فتوے کی ضرورت ہوتی ہے تو عائشہ صدیقہ ؓ سے فتوٰی لیتے تھے۔ تو ابن عباسؓ ساری امت کے استاذ ہیں اور ان کی استاذ حضرت عائشہ ؓ ہیں۔ گویا حضرت عائشہ ؓ علوم و کمالات کے اندر پوری امت کی استاذ ہیں۔ بعض صحابہؓ حضرت عائشہ ؓ سے کہا کرتے تھے ’’ما ھٰذہٖ باَوّل برکتکم یا ال ابی بکر‘‘ اے آل ابی بکر یہ پہلی برکت نہیں۔ تمہاری تو اتنی برکتیں ہیں کہ امت احسان سے تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ ؓ کے سوالات کرنے سے ہزاروں مسئلے کھلے ہیں، بڑی ذہین و ذکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ایسے کیا کرتی تھیں کہ دوسرے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ جواب میں آپؐ علوم ارشاد فرماتے۔ یہ ساری امت پر احسان تھا، اگر وہ سوال نہ کرتیں تو علم نہ آتا۔
مثلاً حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے تین بچے پیدا ہوں اور پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کی حالت میں گزر جائیں۔ برس، دن یا چھ مہینے کے بعد انتقال کر جائیں تو وہ تینوں ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، شفاعت کریں گے اور اس طرح سے کریں گے گویا اللہ تعالیٰ کے اوپر اصرار کریں گے کہ ضرور بخشنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے لیے جہنم کا حکم ہو جائے گا کہ یہ سزا کے مستحق ہیں، جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، یہ تین بچے ملائکہ کے آگے آ کے سامنا روکیں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں آپ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ انہیں جہنم کا حکم ہے، بچے کہیں گے ہم نہیں جانتے یہ ہمارے ماں باپ ہیں، جیسے بچے کی ضد ہوتی ہے اسی طرح ضد کریں گے۔ وہ کہیں گے حکم خداوندی ہے، بچے کہیں گے ہو گا، اللہ نے ہمیں تو معصوم بنایا ہم انہیں نہیں جانے دیں گے ہمارے ہوتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ ملائکہ علیہم السلام کو لوٹنا پڑے گا اور عرض کریں گے الٰہی! یہ بچے راستہ روک رہے ہیں جانے نہین دیتے۔ معلوم ہوتا ہے بچوں کی ضد کے آگے فرشتوں کی نہیں چلے گی۔ جیسے باپ اگر بادشاہ بھی ہو اور بچہ ضد کرے تو بادشاہ کو بھی بچے کی ماننی پڑتی ہے، اس کی حکومت کی ساری قوت دھری رہ جاتی ہے اسی طرح فرشتوں کی طاقت بھی رکھی رہ جائے گی اور وہ مجبور ہو جائیں گے بچے انہیں لوٹا دیں گے تو فرشتے عرض کریں گے کہ خداوند! آپ کا ارشاد تھا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو یہ بچے روک رہے ہیں ضد کر رہے ہیں جانے نہیں دیتے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے ارے نادان بچو! تمہارے ان ماں باپ نے یہ برائی کی یہ برائی کی یہ گناہ کیا یہ معصیت کی یہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یہ کہیں گے ہم نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں اگر آپ کو انہیں جہنم میں ہی بھیجنا ہے تو ہمیں بھی بھیج دیجیئے۔ اب ظاہر ہے کہ معصوم تو جہنم میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے تو ہم انہیں بھی لے کے جائیں گے۔ حق تعالیٰ حجت کریں گے جواب دیں گے بچے وہاں بھی ضد کریں گے اخیر میں حق تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ ارے جھگڑالو بچو! ہمارا پیچھا چھوڑو، لے جاؤ ان ماں باپ کو جنت میں۔ چنانچہ ان کو جنت میں لے جائیں گے۔
یہ حدیث آپؐ نے صدیقہ عائشہ ؓ کو سنائی۔ اس پر صدیقہ عائشہ ؓ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! اگر کسی کے دو بچے اس طرح گزر جائیں؟ فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر سوال کیا اگر ایک بچہ گزر جائے؟ فرمایا ایک کا بھی یہی حکم ہے، حتٰی کہ فرمایا اگر کوئی حمل ضائع ہو جائے بشرطیکہ بچے میں جان پڑ گئی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس طرح سے ضد کر کے اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا۔
اب دیکھئے چھوٹا بچہ جب گزرتا ہے تو ماں باپ پر اور بالخصوص ماں پر کیا گزرتی ہے، اس کے تو وہ جگر کا ٹکڑا تھا، اس نے نو مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے پرورش کیا تھا اور پیدا ہونے کے بعد جب گزر جاتا ہے تو باپ کو تو کچھ جلدی صبر بھی آجاتا ہے مگر ماں کو نہیں آتا۔ اس لیے کہ اس کے لیے تو ایسا ہے جیسے اس کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے ضائع ہو جائے، تو ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن جب یہ حدیث سنے گی کہ یہ میری نجات کا سبب بنے گا تو شاید اسے خوشی پیدا ہو جائے کہ میرے لیے کوئی دکھ نہیں، اگر ضائع ہو گیا تو بلا سے ضائع ہو گیا میرے لیے تو جنت اور نجات کا سامان ہو گیا۔
اگر صدیقہ عائشہ ؓ یہ سوال نہ فرماتیں نہ اتنا علم کھلتا نہ اتنی آسانی پیدا ہوتی۔ ہم تو یہی کہتے کہ اگر تین بچے گزریں تو پھر جنت کا وعدہ ہے اور اگر دو یا ایک ہوا تو پھر جنت کا وعدہ نہیں۔ مگر صدیقہ عائشہ ؓ کے سوال کرنے سے معلوم ہوا کہ دو اور ایک کا بھی یہی حکم ہے بلکہ حمل ساقط ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے بشرطیکہ روح پڑ گئی ہو۔ تو صدیقہ عائشہ ؓ کی ذہانت و ذکاوت اور سوال کرنے سے امت کے لیے کتنی بڑی آسانی پیدا ہو گئی کتنے راستے نکلے۔ تو عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے ہزاروں مردوں کے راستے درست کر دیے اور ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گئیں۔
عورت میں تحمل کی صلاحیت
شادی اور غمی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں آدمی کچھ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ زیادہ غم پڑے جب بھی پاگل سا ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوشی آئے جب بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سنبھال لے وہ بڑا محسن ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسی بھی عورتیں گزری ہیں انہوں نے ایسے وقتوں میں مردوں کو سنبھالا حالانکہ مرد بہ نسبت عورت کے قوی القلب ہوتا ہے، عورت کا دل گو اتنا قوی نہیں ہوتا لیکن عورت میں سمجھ بوجھ اور دین و دیانت ہے تو بڑے بڑے قوی مردوں کو سنبھالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں واقعہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت جابرؓ ان کا چھ سات برس کا بچہ بڑا ہونہار حسین و جمیل بیمار ہوا۔ اس زمانے کے مطابق دوا دارو کی گئی مگر بچہ اچھا نہ ہوا۔ ادھر حضرت جابرؓ کو اچانک سفر پیش آیا اور انہیں ضروری جانا پڑ گیا تو بیوی سے کہا کہ دیکھو مجھے مجبوری کا سفر پیش آ گیا میرا جانا ضروری ہے اور بچے کی حالت ایسی ہی ہے۔ ذرا دوا اور تیمارداری اچھی طرح سے کرنا اور میں جلدی آجاؤں گا، کوئی زیادہ دیر کے لیے مجھے نہیں جانا۔ یہ فرما کر حضرت جابرؓ چلے گئے۔
جب آنے کا دن ہوا تو بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپؓ گھر میں تشریف لائے۔ اور بیوی کی دانش مندی، دیانت داری اور ہوشیاری یہ ہے، ورنہ کوئی اگر آج کی طرح کی بیوی ہوتی جب وہ دیکھتی کہ خاوند آ رہے ہیں تو وہ بڑا رونا شروع کر دیتی تاکہ معلوم ہو بڑا غم پڑا ہوا ہے۔ مگر دانشمند تھیں اس لیے حضرت جابرؓ کے آنے کا وقت ہوا تو اپنے کو سنبھالا اور صورت ایسی بنائی کہ اسے کوئی غم نہیں ہے اور بچے کو اندر لٹا دیا، اس کی لاش پر چادر ڈال دی۔ حضرت جابرؓ آئے تو جیسے عرب کا دستور ہے بیوی نے بڑھ کر استقبال کیا مصافحہ کیا اور اپنے خاوند کے ہاتھ چومے۔ حضرت جابرؓ نے آتے ہی پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ کہا ’’الحمد للہ بعافیۃ و خیر‘‘ خدا کا شکر ہے عافیت میں ہے اور بڑی خیر ہے۔ غلط بات بھی نہیں کہی اس لیے کہ مرنے کے بعد بڑی عافیت و خیر ہوتی ہے۔ تو ایسا جملہ کہا کہ غلط بھی نہ ہو اور خاوند کو تسلی بھی ہو جائے۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ ان کے ہاتھ دھلائے کھانا کھلایا۔ اس لیے کہ آتے ہی صدمے کی خبر سنا دیتی ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ پھر کہاں کا کھانا ہوتا، وہ اس کے سوگ میں لگ جاتے۔
کھانا کھلاتے کھلاتے کہا، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا پوچھو۔ کہا اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھوائے اور اس کی میعاد مقرر کرے کہ برس دن کے لیے رکھواتا ہوں، برس دن کے بعد واپس لے لوں گا۔ تو شریعت کا اس مسئلہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، حکم کھلا ہوا ہے اس کو ٹھیک وقت پر ادا کرنا چاہیئے۔ (پوچھا) اگر امانت کے ادا کرتے ہوئے دل میں گھٹنے لگے اور دل نہ چاہے۔ فرمایا، دل میں گھٹنے کا حق کیا ہے، چیز دوسرے کی ہے، اپنی چیز پر آدمی گھٹے۔ جب دوسرے کی امانت ہے اور دلت مقرر تھا، اب اس نے مانگ لی تو گھٹنے اور غم کرنے کا کیا حق ہے؟ کہا، شریعت کا یہی مسئلہ ہے؟ فرمایا، ہاں مسئلہ یہی ہے۔ کہا، وہ بچہ جو تھا وہ امانت تھا، اللہ نے وہ سات برس کے لیے رکھوایا تھا، کل قاصد پہنچ گیا کہ امانت واپس کر دو، میں نے امانت واپس کر دی، تو ہمیں گھٹنے کا تو کوئی حق نہیں؟ فرمایا نہیں ہے اور بیوی کے ہاتھ چومے اور کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے ایسی تسلی دی کہ مجھے بجائے غم کے خوشی ہے کہ ہم امانت ادا کر چکے اور بوجھ ہلکا ہو گیا۔
یہ عورتیں ہی تھیں جو اس طرح سے تسلی بھی دیتی تھیں۔ مگر یہ ان عورتوں کا کام تھا جن میں حوصلہ اور دین و دیانت کا جذبہ تھا۔ اور اگر عورتیں رواج کے مطابق چلیں تو آنکھوں میں نہ بھی آنسو ہوں گے مگر جب تعزیت کے لیے کوئی آئے تو بنا بنا کے رونا شروع کر دیں گی۔ دوسری آئیں وہ بھی رونا شروع کر دیں گی۔ تیسری آئیں وہ بھی۔ لیکن تحمل کی بات یہ ہے کہ روتے ہوؤں کو تھام لیا جائے، غم زدہ لوگوں کو تھام لیا جائے اور تسلی دی جائے، یہ کام کیا تو مرد کرتے ہیں مگر عورتیں بھی ایسے حوصلے کی گزری ہیں جنہوں نے مردوں کے غموں کو ہلکا کر دیا ہے۔
حضرت خدیجۃ الکبرٰیؓ کا پوری امت پر احسان
حضرت خدیجۃ الکبرٰی رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ پاک ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری امت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی اور عالم غیب سے پہلی بار سابقہ پڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپؐ نے اصلی شکل میں دیکھا ورنہ انسانی صورت میں آتے تھے۔ صحابہؓ میں حضرت دحیہ کلبیؓ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل’ آیا کرتے تھے۔ صحابہؓ دیکھتے تھے کہ دحیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اِدھر ایک اُدھر۔ تو دو مرتبہ اصلی شکل میں حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ ایک تو جب غار حرا میں سب سے پہلی وحی آئی ہے اس وقت اپنی اصلی شکل میں نمایاں ہوئے اور ایک معراج کی شب میں۔ اور یہ دیکھنا اس شان سے تھا کہ ان کے چھ چھ سو بازو ہیں، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک جتنی فضا ہے سب ان کے بدن سے گھری ہوئی ہے، اتنا عظیم قدوقامت ہے کہ سر آسمان پر ہے، پیر زمین پر ہیں، موڈھے جنوب و شمال میں، چھاتی اور سینہ مشرق و مغرب میں ہے۔ گویا پوری فضا جبرائیل علیہ السلام کے بدن سے بھری ہوئی ہے۔ چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، ایک تاج بھی ان کے سر پر رکھا ہوا ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے اس سے شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، اور ایک سبز رنگ کا کپڑا ہے جو ان کے بدن پر پڑا ہوا ہے۔ تو اتنی حسین و جمیل شکل مگر اتنی عظیم دیکھ کر ایک دفعہ آپؐ گھبرا گئے اور آپؐ کے اوپر ہیبت اور لرزہ طاری ہوا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ رجالِ غیب کو اس طرح سے دیکھا اور دیکھا بھی اتنی عظیم شکل میں۔ آپؐ گھبرا گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:
زملونی زملونی زملونی لقد خشیت علٰی نفسی۔
’’مجھے کمبل اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، مجھے ڈر ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا میری جان نکل جائے گی۔‘‘
حضرت خدیجہؓ نے کہا، کیا واقعہ ہوا؟ آپؐ نے واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہؓ نے تسلی دی اور فرمایا:
کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدًا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم و تقری الضیف و تحمل الکل وتعین علیٰ نوائب الحق۔
’’خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی، غریبوں کی مدد اور مہمان نوازی آپؐ کرتے ہیں، مسکینوں کو آپؐ پناہ دیتے ہیں، ساری دنیا کی خیر خواہی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا، آپ بالکل نہ گھبرائیں آپ کی جان نہیں جا سکتی۔‘‘
یہ تو زبان سے تسلی دی اور عمل یہ کیا کہ ہاتھ پکڑ کر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ عرب کے لوگوں میں بہت بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے تھے، مذہبًا نصرانی تھے اس لیے انجیل اور تمام آسمانی کتابیں لکھا بھی کرتے تھے اور ان کو یہ کتابیں یاد تھیں اور ان کے علوم سے واقف بھی تھے۔ مشرکین عرب یا خاندانِ قریش میں ایک یہ تھے جو اہلِ کتاب میں شامل ہوئے اور آسمانی کتابوں کے بڑے زبردست عالم ہوئے۔ حضرت خدیجہؓ حضورؐ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس لے گئیں کہ ان کے حالات کا صحیح پتہ وہ دے سکتا ہے جو عالم ہو اور دینی و تاریخی علوم سے واقف ہو۔ حضرت خدیجہؓ جب ان کے پاس پہنچیں اور کہا ذرا سنیئے یہ آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے؟ ’’اسمع لابن اخیک‘‘ اپنے بھائی کے بچے سے پوچھیئے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ’’یا ابن اخی ما ذرا ترٰی؟‘‘ میرے بھتیجے! کیا بات تم نے دیکھی؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپؐ نے سارا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح غارِ حرا میں بیٹھا ہوا تھا، ایسی شخصیت نمایاں ہوئی، یہ اس کی شکل تھی اور یہ اس نے مجھ سے خطاب کیا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا ’’ابشر ابشر‘‘ خوشخبری حاصل کرو، یہ وہ ناموس ہے جو موسٰی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا اور دیگر پیغمبروں کے پاس آتا تھا۔ خدا نے تم کو اس امت کا پیغمبر بنایا ہے، جس کی خبریں سننے میں آ رہی تھیں وہ تھیں وہ تم ہی معلوم ہوتے ہو، اس لیے تم مت گھبراؤ، یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ اور کہا کہ کاش جب تم تبلیغ کا نام لے کر کھڑے ہو اور اسلام کی دعوت دو میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری مدد اور اعانت کرتا لیکن میں تو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوں۔ سو برس سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، بڑے معمر اور بوڑھے تھے۔
آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا کٹھن معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، یہ معاملہ کوئی بدنی بیماری کا نہیں تھا کہ کوئی بخار آگیا ہو، کھانسی آگئی ہو، یہ روحانی معاملہ تھا اور روحانی معاملہ بھی وہ جو پیغمبروں سے پیش آتا ہے، کسی معمولی ولی کا بھی نہیں بلکہ نبی الانبیاءؐ کا معاملہ تھا۔ اس میں تسلی دینے کے لیے ایک عورت کھڑی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ہمارے زمانے کی کوئی عورت ہوتی وہ گھبرا کے کہتی خدا جانے اب کیا ہو گا جلدی سے کمبل اڑھاؤ اور ایک واویلا شروع ہو جاتا۔ لیکن ان کا گھبرانا تو بجائے خود ہے، اس ذات اقدس کو تسلی دی جو پورے عالم کی سردار بننے والی تھی۔ ان کے دل کو تھامنے کی کوشش کی۔ قول سے الگ تھاما، عمل سے الگ تھاما۔ زبان سے یہ تسلی دی کہ آپ وہ نہیں ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع کرے، آپ تو سرتاپا بزرگ ہی بزرگ خیر ہی خیر ہیں، عادت اللہ یہ ہے کہ ایسی ہستیوں کو اللہ کھویا نہیں کرتا۔ اور عمل یہ کہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ ایک عورت ہی تھیں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا درحقیقت اس پوری امت کو تسلی دینا ہے جو قیامت تک آنے والی ہے۔ گویا اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پوری امت پر احسان ہے۔
میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عورتیں ایسی ایسی بھی گزری ہیں۔ اس لیے عورتوں کا یہ خیال کرنا کہ ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں، کھانا پکا دیا، زیادہ سے زیادہ بچوں کے کپڑے سی دیے اور زیادہ ہوا ان کی تربیت کر دی، اس سے زیادہ ہم ترقی کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ میدان مردوں کا ہے۔ ولی بھی مرد بنے گا، امام بھی مرد بنے گا، مجتہد اور خلیفہ بھی بنے گا، ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ تم چاہو تو مجتہد، ولیٔ کامل بن سکتی ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ الہام کا معاملہ ہو کہ تمہارے اوپر الہام آئے، تم یہ بھی کر سکتی ہو۔ جو ایک بڑے سے بڑے ولی کا حال ہو سکتا ہے وہ ایک عورت کا بھی ہو سکتا ہے بشرطیکہ عورت توجہ کرے، مگر یہ توجہ نہیں کرتیں۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ یہ غلط فہمی رفع ہو جائے کہ عورت کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو گئی کہ ہم نہ دینی ترقی کے لیے ہیں نہ علمی ترقی کے لیے، اس کام کے لیے تو مرد ہیں۔
قصور مردوں کا ہے
اگر برا نہ مانا جائے تو میں کہوں گا کہ اس میں زیادہ قصور مردوں کا ہے۔ یہ خیال انہوں نے اپنے عمل سے پیدا کیا ہے۔ زبان سے تو کسی نے نہیں کہا ہو گا مگر غریب عورتوں کے ساتھ جو طریق عمل برتا گیا ہے کہ نہ ان کو تعلیم و ترقی دینے کا بندوبست نہ دین سکھلانے کا بندوبست۔ گویا عملاً زبانِ حال سے آپ نے انہیں باور کرا دیا کہ تم اس لیے پیدا ہی نہیں کی گئی ہو کہ دینی و اخلاقی ترقی کرو۔ یہ کچھ کریں گے تو ہم کریں گے اور ہم بھی افریقہ میں رہ کے نہیں کریں گے کوئی ہندوستان میں رہ کے ترقی کر لے تو کر لے ہم اس لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے نہ ہماری عورتیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں۔
جب آپ نے اپنے طرزِ عمل سے عورتوں کے راستے بند کر دیے ہیں تو ان غریب عورتوں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ قصور اصل میں مردوں کا ہے اور قیامت کے دن ان مردوں سے باز پرس ہو گی کہ تم نے کیوں تربیت کی طرف توجہ نہیں کی؟ کیوں ان کو تعلیم نہ دی؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ
’’کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ‘‘
تم میں سے ہر شخص بادشاہ ہے اور قیامت کے دن ہر بادشاہ سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی رعیت کو کس طرح رکھا؟ آرام و سکھ سے رکھا یا تکلیف سے؟ صحیح تربیت کی یا نہیں کی؟ دین پر لگایا یا دین سے ہٹایا؟ تو فرمایا ہر گھر کا مرد بادشاہ ہے اور جتنے گھر میں رہنے والے ہیں وہ درحقیقت اس کی رعایا ہیں، اس کے زیر عیال ہیں۔ قیامت کے دن سوال ہو گا کہ گھر والوں کے ساتھ تم نے کس قسم کا برتاؤ کیا؟ ملک کا بادشاہ ہے تو پورا ملک اس کی رعیت ہے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعیت کو کس حال میں رکھا، اس کی آسائش کی خبر لی یا انہیں تکلیفیں پہنچائیں؟ ان کو آبرو بخشی یا انہیں بے آبرو اور بے عزت کیا؟ ان کو ایذا پہنچائی یا ان کی راحت رسانی کا سامان کیا۔
یہ ہر بادشاہ سے سوال ہو گا۔ استاذ سے اس کے شاگردوں کی نسبت سوال ہو گا کہ تیرے شاگرد تیرے حق میں بمنزلہ رعیت کے تھے، تو ان کا بادشاہ تھا، وہ تیری حکم برداری کرتے تھے، تو نے ان پر کیا کیا حکم چلایا؟ شیخ سے اس کے مریدین کی نسبت سوال ہو گا کہ مریدین بمنزلہ رعیت کے تھے، تو حکم کرنے والا تھا، تجھے منوانے کا مقام دیا گیا تھا اور وہ ماننے والے تھے، تو نے کیا کیا چیزیں منوائیں؟ تو نے ان سے دین منوایا یا بری چیزیں ان سے منوائیں؟ غرض ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، تو آپ سے اور مجھ سے بھی سوال ہو گا۔ عورتوں کے بارے میں بھی سوال ہو گا کیونکہ وہ ہمارے زیرتربیت اور زیرعیال ہیں۔
رسول اللہؐ کی وصیت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ عورتوں کی طرف دی ہے حتٰی کہ عین وفات کے وقت جو آخری کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ
’’اتقوا اللہ فی النسآء‘‘
اے لوگو! عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ امانتیں ہیں جو تمہارے سپرد کی کی گئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم امانت میں خیانت کرو اور قیامت کے دن تم سے بازپرس ہو۔ یہ آخری کلمہ ہے جو عین وفات کے وقت فرمایا ہے وہ یہ تھا کہ عورتوں کی فکر کرو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، ان کو خراب نہ کر دیا جائے، ان کی تربیت نہ تباہ ہو جائے، ان کا دین نہ برباد ہو جائے اور دنیا نہ خراب ہو جائے۔ تو جس ذاتِ اقدس نے خود عورتوں کے بارے میں اتنی توجہ کی اس کی امت کا بھی فرض ہے کہ وہ توجہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ
ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا الطفکم اھلا۔
تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم وہ مسلمان ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور عورتوں، بیویوں کے ساتھ لطف و مروّت اور مدارت کا برتاؤ کرتا ہو۔ مطلب یہ کہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتی اور سختی سے پیش آئے وہ قابلِ تکریم نہیں ہے، اس حدیث کا حاصل یہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور پوری توجہ فرمائی اور عین وفات کے وقت آپؐ نے جو نصیحت ارشاد فرمائی وہ عورتوں کے بارے میں تھی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ امت کے لیے نبی اکرمؐ نے جہاں اتنا خیال کیا، امت کیا خیال کر رہی ہے؟ امت نے یہ کیا کہ طرزِ عمل سے باور کرا دیا کہ تم نہ دینی ترقی کے قابل، نہ دینی عمل کے قابل، یہ تمہارا کام ہی نہیں۔ بس تمہارا کام یہ ہے اگر تم غریب ہو تو گھر بیٹھ کے کھانا پکاؤ، اور اگر تم دولت مند ہو تو کھانا ملازمہ پکا لے گی، تم اچھے کپڑے پہن لیا کرو، بہترین زیور پہن لیا کرو اور جو جی میں آئے آرائش زیبائش کر لیا کر، بس قصہ ختم ہو گیا، زیادہ سے زیادہ یہ کیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بدنوں کو تو سنوار دیا لیکن دلوں کو بھی سنوارا ہے؟ بدن کی آرائش و زیبائش تو چند دن کی بہار ہے، یہ چند دن میں ختم ہونے والی ہے۔ خدا بھلا کرے بخار کا، تین دن میں بتلا دیتا ہے، ساری جوانی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اگر آدمی جوانی کے اوپر ناز کرے اور چہرے کی تازگی اور رونق پر اترائے تو تین دن کا بخار بتلا دیتا ہے کہ جوانی کی یہ حقیقت تھی۔ چہرے کی سرخی بھی ختم، منہ پر جھریاں پڑ گئیں اور تین دن میں بخار سے ایسا حال ہو گیا اور بخار نے بتلا دیا کہ سب سے بڑا مربّی اور ناصح میں ہوں، یہ بتلا دیتا ہے کہ جس کے لیے سارا سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کی یہ قدر و قیمت ہے۔ اسی واسطے اہل اللہ نے اس کی خاص طور پر تاکید کی ہے کہ صورتوں کے حسن و جمال میں زیادہ مت گھسو، سیرت کے حسن و جمال کو دیکھو، اخلاق کی پاکیزگی کو دیکھو۔
مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کی خانقاہ میں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی آتے تھے۔ ایک شخص آیا، ابھی بے چارہ نیا تھا، بزرگی نے اس کے دل میں گھر نہیں کیا تھا، شیخ سے بیعت ہوا۔ شیخ نے اسے اللہ اللہ بتا دی، اس نے بھی ذکر اللہ شروع کر دیا۔ اور طریقہ یہ تھا کہ خانقاہ میں جتنے مریدین ٹھہرے ہوئے تھے ان کا کھانا شیخ کے گھر سے آتا تھا۔ ایک باندی تھی جو کھانا تقسیم کر جاتی تھی۔ یہ مرید جو نووارد تھے، باندی انہیں کھانا دینے کے لیے آئی، باندی ذرا اچھی صورت کی تھی، ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو گئی، اب جب وہ کھانا لے کے آئے یہ اسے گھورنا شروع کریں۔ شیخ کو پتہ چل گیا کہ یہ باندی کی صورت کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جتنا صورت و شکل میں الجھیں حقیقت اتنی کم ہو گی اور ذکر اللہ وغیرہ چھوٹ گیا، بس یہ نگاہ بازی رہ گئی، جب وہ آئے تو اسے گھور رہے ہیں، نہ اللہ کا نام اور نہ ذکر۔ عادت اللہ یہی ہے کہ بندہ صورتوں میں جتنا الجھتا ہے حقیقت سے اتنا ہی بے خبر بن جاتا ہے، جب صورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا حقیقت کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ صورت کے دیکھنے میں لگ گئے، اور جو حقیقت تھی اللہ اللہ کرنا اور یادِ خداوندی اس سے غفلت شروع ہو گئی۔
شیخ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے مرید اس بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ انہوں نے بڑی تدبیر سے علاج کیا، انہیں بلا کر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، ایسا مت کرو۔ بلکہ ایک تدبیر اختیار کی اور ہنسی کی تدبیر اختیار کی اور ان کی اصلاح بھی ہو گئی۔ وہ یہ کہ دستوں کی ایک دوا لا کر اس باندی کو کھلا دی، جمال گھوٹا یا کوئی دوسرا مسہل۔ صبح سے شام تک اسے بڑی تعداد میں دست آ گئے اور باندی کو یہ حکم دیا کہ ایک چوکی رکھ دی گئی ہے اس پر جا کر حاجت کرنا۔ وہ بیچاری ہر دست منٹ کے بعد جاتی۔ شام کو جب وہ چہرے کی سرخی باقی نہ رہی، ہڈی کو چمڑا لگ گیا، صورت دیکھو تو دیکھ کے نفرت آئے اور وہ جو گلاب سا چہرہ کھل رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا، ایک زردی سے چھا گئی۔ شیخ نے اب اس کو کہا کہ اس مرید کے پاس کھانا لے کے جا اور تیرے ساتھ جو معاملہ کرے مجھے اس کی اطلاع دینا۔ اب وہ کھانا لے کے آئی تو انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب وہ آئے اور میں اس کو گھوروں۔ اور اب جو آئی تو دیکھا کہ ہڈیاں نکلی ہوئیں، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئیں، سرخی کے بجائے زردی چھائی ہوئی، انہیں بڑی نفرت پیدا ہوئی، کہا رکھ دے کھانا اور چلی جا جلدی سے یہاں سے، وہ بیچاری کھانا رکھ کے چلی گئی۔ شیخ سے اس نے جا کے یہ کہا، یہ اس نے کہا۔ اور کہا بجائے اس کے کہ مجھے دیکھے کہا چلی جا یہاں سے۔
شیخ سمجھ گیا کہ علاج ہو گیا۔ شیخ تشریف لائے اور اس مرید سے فرمایا کہ میرے ساتھ تشریف لے چلیئے۔ انگلی پکڑ کے لے گئے۔ وہ جو قدمچہ رکھا ہوا تھا جس میں کثیر تعداد دستوں کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ فرمایا یہ ہے آپ کا معشوق، اسے لے جائیے۔ اس لیے کہ جب تک یہ باندی میں موجود تھا باندی سے محبت تھی، اب یہ نکل گیا اور تو کوئی چیز نہیں نکلی، آپ کو نفرت ہو گئی۔ معلوم ہوا اس باندی سے محبت نہیں تھی اس گندگی سے محبت تھی۔ اس گندگی کو احتیاط سے لے جائیے اور صندوق میں رکھیے، یہ آپ کا معشوق و محبوب ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ صورتوں کا عشق گندگی کا عشق ہے، سیرت کا عشق پاکیزگی کا عشق ہے، اعلیٰ ترین سیرت اخلاق ہیں، محبت کے قابل یہ چیز ہے۔
صورت نہیں سیرت
بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صورت کی خوبی فتنے پیدا کرتی ہے اور سیرت کی خوبی امن پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حدیث میں فرمایا گیا
فاذا قد اعطی شطر الحسن۔
آدھا حسن اللہ نے ساری دنیا کو دیا اور آدھا حسن و جمال تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے حسین و جمیل تھے لیکن یوسف علیہ السلام پر جتنی مصیبتیں آئیں وہ صورت کے حسن کی وجہ سے آئیں۔ بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچے گئے، نو برس تک جیل خانہ بھگتا، یہ ساری صورت کی مصیبت تھی۔ اور جب مصر کی سلطنت ملنے کا وقت آیا اس وقت خود حضرت یوسفؑ نے کہا ’’اجلعنی علٰی خزآئن الارض‘‘ مجھے مصر کی سلطنت دے دو تو وجہ یہ نہیں بیان کی ’’انّی حسین جمیل‘‘ میں بڑا خوبصورت ہوں اس لیے مجھے بادشاہ بنا دو۔ بلکہ یوں فرمایا ’’اِنّیْ حَفِیْظ عَلِیْم‘‘ مجھے سلطنت بخش دو اس واسطے کہ میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں کہ سلطنت کس طرح سے چلتی ہے، میں اپنے علم و کمال سے سلطنت چلا کے دکھاؤں گا۔ تو مصیبتوں کا جب وقت آیا تو حسن و جمال سامنے آیا۔ اور سلطنت ملنے کا وقت آیا تو اندرونی سیرت، علم و کمال سامنے آیا۔ اس لیے صورت کی خوبیاں فتنے میں مبتلا کرتی ہیں اور سیرت کی خوبیاں دنیا میں امن پیدا کرتی ہیں۔
میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اگر غریب گھرانے کی عورت ہے تب تو بڑے سے بڑا کام مردوں کی طرف سے کیا سپرد ہوتا ہے؟ یہ کہ کھانا پکا دے، گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پال پرورش کر دے، اس کے فرائض ختم ہو گئے۔ اور اگر امیر گھرانے کی عورت ہے تو وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گی، وہ ملازمہ کرے گی، کھانا بھی وہ پکائے گی، ان کا کام یہ ہے کہ ذرا اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا زیور پہن لیا، ذرا اور آزاد ہوئیں تو تفریح کے لیے بازار بھی ہو آئیں، یہ کام کر لیا اور زندگی کے فرائض ختم ہو گئے۔ آگے یہ کہ تمہاری سیرت کیسی ہے؟ تمہارا قلب کیسا ہے؟ اخلاق کیسے؟ اس میں علم ہے یا نہیں؟ آخرت کا تعلق ہے یا نہیں؟ اللہ کے سامنے جانے کا کچھ خطرہ تمہارے سامنے ہے یا نہیں؟ قبر و حشر میں کیا گزرے گی؟ انجام کیا ہو گا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں، بس کھا لیا، پی لیا، عمدہ لباس پہن لیا، بہتر سے بہتر زیور پہن لیا اور فرائض ختم ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے ہاں سوال ہو گا کہ تمہیں بادشاہ بنایا گیا تھا کیا اس لیے کہ رعیت کو اچھا کھلا دو، پہنا دو، اور ہم سے غافل کر دو؟ اس لیے تمہیں بادشاہ بنایا گیا تھا کہ مقصد کی طرف متوجہ کرو، وہ یہ کہ ہماری طرف متوجہ کرتے، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ نہیں کیا تو تم سزا کے مستحق ہو۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں عورتوں کا کوئی قصور نہیں، یہ سارا مردوں کا قصور ہے کہ نہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں نہ ان کی تربیت کا۔ ان کی دلداری کا بڑے سے بڑا طریقہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو اُن کو خواہش ہو وہ پوری کر دو۔ کپڑے زیور دے دو بس فرض ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کرتے کہ ان کے دل کو سنواریں، ان کی روح میں آراستگی پیدا کریں۔ کیا قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال نہیں ہو گا؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ضرور پوچھا جائے گا، ضرور پرسش ہو گی، اس جواب دہی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب عورت کی گود علم و کمال سے خالی ہو گی تو بچے میں علم کہاں سے آئے گا؟ بچہ تو ماں کی گود سے علم حاصل کرتا ہے، وہاں جہالت ہے تو وہ بھی جاہل ہو گا۔ وہاں محض ظاہری ٹیپ ٹاپ کی خواہش ہے، بچے میں بھی یہی ٹیپ ٹاپ پیدا ہو گی، اسے بھی دل کے سنوارنے کی کوئی فکر نہیں ہو گی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آگیا اور وہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ وہ اس کا ہے کہ اگر عورت دیندار بننا چاہے اور اس کو بنانا چاہیں تو بڑے بڑے آرام اور عیش میں رہ کر بھی دیندار بن سکتی ہے۔ اور بددین بننا چاہے تو فقر و فاقہ میں بھی بددین بن سکتی ہے۔ دین کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی بھک منگا بن جائے تو دیندار بنے گا اور اگر کوئی کروڑ پتی ہو گیا تو وہ دین دار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غلط ہے۔ دیندار بننا چاہے تو کروڑ پتی بن کے بھی دیندار بن سکتا ہے اور نہ بننا چاہے تو فاقہ مست ہو پھر بھی بددین بن سکتا ہے، اس پر میں واقعہ عرض کر رہا ہوں۔
وہ یہ کہ کابل کے بادشاہوں میں امیر دوست محمد خان بہت دیندار بادشاہ گزرے ہیں۔ امیر امان اللہ خان مرحوم کے باپ امیر حبیب اللہ خان تھے اور حبیب اللہ خان کے باپ امیر عبد الرحمٰن تھے، ان کے باپ دوست محمد خان ہیں۔ ان کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں کسی دوسرے بادشاہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور فوج لے کر چڑھ دوڑا۔ امیر صاحب کو اس سے صدمہ بھی ہوا اور دکھ بھی کہ ایک بادشاہ نے میری سلطنت پر حملہ کر دیا، ممکن ہے کہ بادشاہت بھی ختم ہو اور آنے والا ملک کو برباد کر دے۔ اسی فکر میں شاہی محل میں اندر تشریف لائے، ان کی بیگم کھڑی ہوئی تھیں، بیگم سے یہ کہا کہ آج ایسی خبر آئی ہے کہ کسی بادشاہ نے حملہ کیا ہے، میں نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیج دیا ہے تاکہ وہ جا کے دشمن کا مقابلہ کرے۔ بیگم نے کہا ٹھیک کیا اور گبھرائیے مت، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ غرض اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیج دیا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرے اور اس کو ملک میں نہ آنے دے اور اسے دور دھکیل دے، شہزادہ فوج لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن امیر صاحب گھر میں آئے اور چہرے پر غم کا اثر، بیگم سے کہا کہ آج ایک بڑے صدمے کی خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ میرا شہزادہ ہار گیا اس نے شکست کھائی، اور دشمن ملک کے اندر چڑھا ہوا آ رہا ہے اور میرا بیٹا شکست کھا کر واپس بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے، ملک بھی جا رہا ہے اور یہ بات بھی پیش آگئی۔ بیگم نے کہا یہ بالکل جھوٹی خبر ہے اور آپ اس کا بالکل یقین نہ کریں۔ اس نے کہا جھوٹی نہیں ہے یہ تو سرکاری پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے، محکمہ سی آئی ڈی کی اطلاع ہے۔ بیگم نے کہا آپ کا محکمہ بھی جھوٹا ہے اور سی آئی ڈی بھی آپ کی جھوٹی ہے، یہ خبر غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔
اب امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلطنت کی باضابطہ اطلاع ہے، یہ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ خبر جھوٹی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ باضابطہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ امیر نے کہا کہ اب اس عورت سے بیٹھ کر کون جھک جھک کرے، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، نہ کوئی دلیل نہ کوئی حجت، میں دلائل بیان کر رہا ہوں کہ محکمہ کی اطلاع اور ضابطہ کی خبر، اس نے کہا سب جھوٹے۔ اب اس سے کون بحث کرے۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے:
اَوَمَن یُّنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَۃِ وَھُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِیْنٍ۔
فرمایا کہ عورت میں کچھ عقل کی کمی ہوتی ہے، جب بحث ہوتی ہے تو وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بچپن سے زیوروں کی جھنکار میں پرورش پاتی ہے۔ جب ابتداء ہی سے رات دن سونا چاندی دل میں گھس گیا تو علم اور کمال کہاں سے گھسے گا۔ ایک چیز گھس سکتی ہے، یا سونا گھس جائے یا علم۔ ذرا دودھ پینا چھوٹا تو اس کے کان میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں سونے کی بالی پڑ جائے اور ذرا بڑی ہوئی تو ناک میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں سونے کی بالی بھی ڈال دو اور زیادہ ہوا تو گلے میں سونے کا طوق ڈال دیا۔ ہاتھوں میں سونے کی ہتھکڑیاں ڈال دیں اور پیروں میں سونے کی بیڑیاں ڈال دیں۔ غرض سونے چاندی کی قیدی۔ اور واقعی اگر عورتوں سے یوں کہا جائے کہ تمہارے سارے بدن میں کیلیں ٹھونکی جائیں گی مگر وہ سونے کی ہوں گی، فورًا راضی ہو جائیں گی، جلدی کرو ٹھونک دو مگر کیل سونے چاندی کی ہونی چاہیئے۔ اس درجہ سونے اور چاندی کی محبت میں گرفتار ہیں کہ بدن چھدوانے کو تیار ہیں مگر سونا اور چاندی ہو۔ جب اس درجے پر بات ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو قرآن نے فرمایا ’’او من ینشؤا فی الحلیۃ وھو فی الخصام غیر مبین‘‘ وہ جو سونے اور چاندی میں نشوونما پاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علمی قوت نہیں پیدا ہوتی، جب خاوند سے بحث ہوتی ہے، وہ تو حجتیں پیش کرتا ہے اور یہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتی ہے کہ نہیں یوں ہو گا۔
تو امیر صاحب نے دیکھا کہ بھئی میں حجت بیان کر رہا ہوں، سرکاری خبریں دے رہا ہوں، یہ کہتی ہے سب غلط ہیں۔ اب اس عورت سے کون بحث کرے، محل سرائے سے واپس چلے آئے۔ دوسرے دن بڑے خوش خوش آئے اور کہا مبارک ہو، جو تم نے کہا تھا بات وہی سچی نکلی۔ خبر یہ آئی ہے کہ میرا شہزادہ فتح پا گیا اس نے دشمن کو بھگا دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ بیگم نے کہا الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے میری بات اونچی کی اور میری بات سچی کر دکھائی۔ امیر نے کہا، آخر تم کہیں کیسے معلوم ہوا تھا جو تم نے کل یہ حکم لگا دیا کہ میرا محکمہ بھی جھوٹا، سی آئی ڈی اور پولیس بھی جھوٹی، تو تمہیں کوئی الہام ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے الہام سے کیا تعلق، اول تو عورت ذات، پھر ایک بادشاہی تخت پر بیٹھنے والی، یہ بزرگوں کا کام ہے کہ انہیں الہام ہو، بھلا مجھے الہام سے کیا تعلق؟ میں ایک معمولی عورت۔ انہوں نے کہا، آخر تم نے اس قوت سے کس طرح کہہ دیا کہ سب بات غلط ہے اور واقعہ بھی وہی ہوا کہ وہ غلط ہی ثابت ہوئی۔ اس نے کہا، اس کا ایک راز ہے جس کو میں نے اب تک کسی کے سامنے نہیں کھولا اور نہ اسے کھولنا چاہتی ہوں۔
امیر نے کہا وہ کیسا راز ہے؟ اب امیر صاحب سر ہو گئے کہ آخر ایسا کونسا راز ہے جو خاوند سے بھی چھپا ہوا رہ جائے۔ اس نے کہا صاحب! کہ ایسی بات ہے کہ میں اس کو کہنا نہیں چاہتی۔ ’’الانسان حریص فی ما منع‘‘ مثل مشہور ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کی اور زیادہ حرص بڑھتی ہے کہ آخر اس میں کیا ہو گا؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ اب تو بتانا پڑے گا۔ جب بہت زیادہ سر ہو گئے تو اس نے کہا آج تک میں نے یہ راز چھپایا اب کھولے دیتی ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ مجھے اس کا کیوں یقین تھا کہ شہزادہ فتح پا کے آئے گا یا قتل ہو گا مگر شکست نہیں کھا سکتا، دشمن کو پیٹھ دکھا کے نہیں آ سکتا۔ یہ میرا یقین کس بنا پر تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اس نو مہینے میں ایک مشتبہ لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گی، رزقِ حلال کی کمائی میرے پیٹ میں جائے گی۔ اس لیے کہ ناپاک کمائی سے خون بھی ناپاک پیدا ہوتا ہے اور ناپاک خون سے اخلاق بھی گندے اور ناپاک پیدا ہوتے ہیں تو میں نے عہد کیا اور نو مہینے اسے پورا کیا کہ لقمۂ حرام تو بجائے خود ہے میں نے کوئی مشتبہ لقمہ بھی پیٹ میں نہیں جانے دیا، خالص حلال کی کمائی سے پیٹ کو بھرا۔ ایک تو میں نے یہ عہد کیا، اس کو لازم رکھا اور اس پر عمل کیا۔
دوسری بات میں نے یہ کی کہ جب یہ پیدا ہو گیا تو ہزاروں دودھ پلانے والی ملازمات تھیں، میں نے اس کو انہیں نہیں دیا، اپنا دودھ پلایا، دودھ پلانے کا طریقہ یہ تھا، جب یہ روتا، میں پہلے وضو کرتی، دو رکعت نفل پڑھتی، اس کے بعد اسے دودھ پلاتی، دعائیں بھی مانگتی۔ تو ادھر تو اندر پاک غذا پھر اللہ کی طرف توجہ، غرض دودھ بھی پاک، اس سے پیدا ہونے والا خون بھی پاک، اور پاک خون سے پیدا ہونے والے اخلاق بھی پاک۔ اس لیے اس کے اندر بد اخلاقی نہیں ہو سکتی۔ پشت دکھلا کر آنا اور بزدلی کرنا یہ کمینے اخلاق میں سے ہے۔ شجاعت اور بہادری یہ پاکیزہ اخلاق میں سے ہے، جب اس کا خون پاک تھا تو یہ کیسے ممکن تھا یہ بزدل بنتا؟ یہ ممکن تھا یہ قتل ہو جاتا، شہید ہو جاتا۔ مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ پشت کے اوپر زخم کھا کر واپس آتا اور بزدلی دکھلاتا، جب اس کے خون میں ناپاکی نہیں تو اس کے افعال میں ناپاکی کہاں سے آئے گی؟ یہ وجہ تھی جس کی بنا پر میں نے دعوٰی کر دیا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ شکست کھا کے آئے۔ ہاں آپ یہ کہتے کہ شہید ہو گیا ہے میں یقین کر لیتی کہ وہ قتل ہو گیا۔ اس بنا پر میں نے یہ دعوٰی کیا تھا آج میں نے یہ راز کھولا۔
آپ اندازہ کریں کہ امیر دوست محمد خان کی بیوی ایک اقلیم کی ملکہ ہیں ہزاروں فوجیں اور سپاہ، حشم و خدم اس کے سامنے ہیں اور وہ جب تختِ سلطنت پر بیٹھ کر اتنی متقی بن سکتی ہے تو ہماری بہو بیٹیاں معمولی گھرانے میں رہ کر کیوں نہیں متقی بن سکتیں؟ ہمارے پاس کون سی ایسی دولت ہے؟ ہم اگر لکھ پتی یا کروڑ پتی بنیں سارے افریقہ کے مالک تو نہیں ہو گئے، ہفت اقلیم کے بادشاہ تو نہیں ہو گئے۔ ایک ملکہ اور بادشاہ کی بیوی جب یہ تقوٰی دکھلا سکتی ہے تو میری بہنیں کیوں نہیں تقوٰی دکھلا سکتیں؟ میری بیٹیاں کیوں نہیں یہ تقوٰی دکھلا سکتیں؟ ان کے پاس تو اتنی دولت بھی نہیں کہ دولت کے قصہ سے کوئی وقت فارغ نہ ہو۔ فارغ وقت بھی ہوتا ہے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ اگر دیندار بننا چاہیں، عورت ہو یا مرد، کروڑ پتی بن کے بھی بن سکتا ہے، نہ بننا چاہے تو فاقہ زدہ ہو کے بھی دیندار نہیں بن سکتا، بددین رہے گا۔ یہ اپنے قلب پر موقوف ہے اور قلب میں یہ جذبہ جب پیدا ہو گا جب اس قلب کی تربیت کی جائے، اس کو تعلیم دی جائے، اس میں علم ڈالا جائے، اس میں اللہ کی عظمت پیدا کی جائے۔ اس میں حلال کی کمائی کی رغبت پیدا کی جائے، ناجائز باتوں سے بچنے کے جذبے پیدا کیے جائیں، تب قلب میں صلاحیت آئے گی، پھر جو اولاد تربیت سے پیدا ہو گی وہ صالحین میں سے ہو گی، وہ خودبخود تقوٰی و طہارت اور نفس کی پاکیزگی لیے ہوئے پیدا ہو گی۔
تو واقعہ یہ ہے کہ بنیاد عورت سے چلتی ہے مگر عورت کو بنانے کی بنیاد مردوں سے چلتی ہے۔ انجام کار ہماری اور آپ کی کوتاہی نکلتی ہے، ہماری بہنوں کا کوئی قصور نہیں۔
بچہ کی تربیت
یہ میں کوئی ان بہنوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ بھئی آج فقط عورتوں کا جلسہ ہے اس لیے ایسی بات کہہ دوں جس سے وہ ناراض نہ ہوں۔ ایسا نہیں بلکہ امر حقیقت ہے کہ اگر ہم صحیح تربیت کریں، یہ ہمارا فرض ہے، چار پانچ برس کی بچی بے چاری کیا جانتی ہے جس راہ پر آپ ڈال دیں گے پڑ جائے گی۔
امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوا بچہ اسی وقت سے تربیت کے قابل بن جاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب چار پانچ برس کا ہو گا جب اس کو تعلیم و تربیت دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی تربیت کا وقت آجاتا ہے، اس وجہ سے کہ بچہ مہینے بھر کا ہے اسے ظاہر میں کوئی عقل و شعور اور تمیز کچھ نہیں لیکن اس کے سامنے کوئی برا کلمہ مت کہو اور کوئی بری ہیئت بھی اس کے سامنے مت اختیار کرو، اس لیے کہ اسے ہوش تو نہیں مگر اس کا قلب ایسے ہے جیسے سفید کاغذ، آنکھ کے راستے جو ہیئت جائے گی وہ اس کے قلب کے اوپر جا کے چَھپ جائے گی۔ آپ برا کلمہ کہیں گے یا گالم گلوچ کریں گے وہ کان کے راستے سے جا کر اس کے دل پر چَھپ جائے گا، جب وہ ہوش سنبھالے گا تو وہی باتیں بکتا ہوا ہو گا۔
غرض تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اسے کیا شعور ہے؟ جو چاہے اس کے سامنے کہہ دو اور جو چاہو کر گزرو، جو چاہو ہیئت بنالو، اسے کیا شعور؟ یہ درست ہے کہ اسے تمیز اور شعور نہیں ہے مگر یہ چیز کان آنکھ کے راستے سے جا کر دل پر چَھپتی ہے۔ تو امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کے سامنے بات بھی کرو تو تہذیب اور شائستگی کی کرو۔ کوئی بے جا بات مت کرو، وہ بے جا بات اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور جب کوئی ہیئت دکھلاؤ تو بری ہیئت مت دکھلاؤ، اچھی ہیئت دکھلاؤ، آنکھ کے راستے سے وہی ہیئت اس کے دل پر چَھپے گی۔ اس بنا پر کہتے ہیں کہ تربیت پانچ برس کی عمر میں نہیں ہوتی، پیدا ہوتے ہی تربیت کا موقع آجاتا ہے۔
بچہ نقال ہوتا ہے
یہ جب ہو گا جب خود ماں باپ میں تقوٰی و پاکیزگی اور احتیاط موجود ہو گی۔ جتنی یہ پاکیزگی برتیں گے اتنی ہی پاکیزگی بچے کے قلب میں بھی پیدا ہو گی۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے بچے عموماً گالیاں دیتے ہوئے بڑھتے ہیں، شہروں کے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیہات میں خود ماں باپ گالیاں بکتے ہیں، بچے کے دل میں بھی وہی چَھپتی رہتی ہیں، شہر میں ذرا تہذیب کے کلمے ہوتے ہیں، وہ چَھپتے رہتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ شریعتِ اسلام نے آداب میں سے یہ رکھا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے سب سے پہلے بندوبست نہ روٹی کا کیا کہ اسے دودھ پلاؤ، نہ کپڑے کا کیا، خیر یہ بھی پہنا دے، پہلا بندوبست یہ کیا کہ اس کے (غسل دینے اور ظاہری آلودگی سے پاکی کے بعد) دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر۔ اذان کہنا ایسا ہے جیسے دیوار کے سامنے کہے تو دیوار کو کیا خبر؟ تو یہی بات آتی ہے کہ اسے خبر تو نہیں ہے مگر کان کے راستے جب ’’اشھد ان لا الہ الا اللہ‘‘ پہنچے گا تو دل میں ’’اللہ اکبر‘‘ اللہ سب سے بڑا ہے یہ کلمہ جب پہنچے گا تو دل میں اس کی چھاپ لگ جائے گی۔ جب آپ ’’اشھد ان محمدًا رسول اللہ‘‘ کہیں گے دل پر رسالت پر ایمان لانا چَھپ جائے گا۔ جب ’’حی علی الصلٰوۃ‘‘ کہیں گے کہ آپ نماز کی طرف دوڑو، یہی جملہ چَھپ جائے گا۔ تو دائیں کان کو آپ نے توحید و رسالت، عمل صالح اور اللہ کی عظمت و بڑائی سے بھر دیا اور بائیں کان کو تکبیر سے بھر دیا۔ اس میں اللہ و رسولؐ اور دین کی عظمت دل میں بٹھلائی تو اذان و تکبیر ہو گئی۔
علماء لکھتے ہیں کہ اس اذان اور تکبیر کی نماز کونسی ہے؟ جو جنازہ کی نماز آپ پڑھیں گے اس کی یہ اذان و تکبیر ہے۔ دنیا میں آتے ہی اذان دی گئی، تکبیر بھی کہی گئی اور دنیا سے جاتے ہوئے جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ یہ اس کی اذان و تکبیر تھی تاکہ ایک مومن بچے کی ابتدا اور انتہا دونوں اللہ کے نام پر ہوں۔ تو اللہ اکبر سے زندگی شروع ہوئی اور اسی پر ختم ہو گئی۔ زندگی کا اول و آخر خدا کے نام سے چلا۔ اس کی بنا یہی ہے کہ ابتدا ہی جو اس کے دل میں چَھپے اللہ کا نام چَھپے، کوئی گالم گلوچ اور برا کلمہ نہ چَھپے۔
اب اگر آپ تربیت دیں گے تو دل میں پیدا ہوتے ہی بیچ تو آپ نے ڈال دیا۔ اب نماز کے لیے کہیں گے تو بیج موجود ہے اس میں پھل پھول لگنے شروع ہو جائیں گے، عملِ صالح شروع ہو جائے گا۔ ہاں خدانخواستہ تربیت نہ کی تو وہ جو بیچ ڈالا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ زمین میں آپ بیج ڈال دیں لیکن نہ پانی دیں نہ دھوپ سے بچائیں، بیج جل کر ختم ہو جائے گا۔ امید بھی نہیں رہے گی کہ اس میں کوئی درخت پیدا ہو۔ اس لیے بیج تو توحید و رسالت کا پیدا ہوتے ہی ڈال دیا جاتا ہے، آگے ماں باپ کو حکم ہے کہ ’’مروا صبیائکم اذا بلغوا سبعًا‘‘ بچوں کو نماز کا حکم دو، جب وہ سات برس کے ہو جاویں، اور مار کر پڑھاؤ جب وہ درس برس کے ہو جائیں۔ یہ گویا تربیت اور آبیاری ہے کہ بیج وہاں ڈالا تھا اب پانی دینا شروع کرو۔ دھوپ سے بچاؤ تاکہ وہ بیج پھل لائے اور درخت بن جائے۔ یہ تربیت ہو گی تو اس کے بچے اور بچیاں بھی مستحق ہیں، لڑکے اور لڑکیاں بھی۔ آگے ماں باپ قصوروار ہیں اولاد قصوروار نہیں ہے۔ اولاد جب قصوروار بنے گی جب وہ عاقل بالغ ہو۔ شریعت کا خطاب متوجہ ہو، پھر اس سے مؤاخذہ ہو گا۔ مگر ابتدائی تعلیم نہ دینے کا مواخذہ ماں باپ سے ہو گا کہ کیوں نہ تم نے صحیح راستے پر ڈالا؟ کیوں غلط راستے پر ڈالا؟
عورتوں کی صحیح تربیت کی ضرورت
تو اس کی ضرورت ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا بھی صحیح طریق پر بندوبست کیا جائے مثلاً ہمارے ہاں یہ قدیم زمانے میں دستور تھا بلکہ اب بھی کچھ قصبات میں ہے کہ اسکول یا کالج نہیں قائم ہوتے بلکہ محلے میں جو بڑی بوڑھیاں ہیں اور وہ پڑھی لکھی ہوئی ہیں تو محلے کی بچیاں ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھ رہی ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہی ہیں، مسئلے مسائل کے لیے ان کو بہشتی زیور پڑھایا جا رہا ہے، یہ ان کی گھریلو تعلیم ہو جاتی تھی۔ جب یہ چیز کم ہو گئی تو مدرسے کھلے، بچیاں وہاں پڑھنے چلی جاتی ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کی طرف توجہ ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو جیسے خودرو درخت ہوتے ہیں کہ جدھر کو ان کا جی چاہے چلی جائیں۔ بہرحال ان کو گھریلو تعلیم دی جائے، جو عورتیں قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں، یا اردو جانتی ہیں، یا انہیں اپنی زبان میں مسائل معلوم ہوں، یا کوئی کتاب ہے وہ پڑھائیں تاکہ ابتداء سے مسئلے مسائل کا علم ہو۔
اس لیے کہ شریعتِ اسلام نے علم کے سلسلے میں دو درجے رکھے ہیں۔ ایک درجہ ہر انسان پر مرد ہو یا عورت واجب ہے، اور ایک درجہ فرضِ کفایہ ہے کہ سو میں سے ایک ادا کر دے تو سو کے لیے کافی ہے۔
- وہ حصہ جو ہر ہر شخص پر واجب ہے وہ ضروریاتِ دین کا ہے کہ جس سے عقیدہ معلوم ہو جائے، اخلاق کا پتہ چل جائے، حقوق کی ادائیگی، ماں باپ، اولاد، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اللہ و رسولؐ کا کیا حق ہے؟ کچھ عبادت، کچھ معاشرت، کچھ اخلاق، کچھ اعتقادات، یہ سیکھنے تو واجب ہیں۔ خواہ مرد ہو یا عورت۔
- اور ایک ہے پورا عالم بننا، یہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، سو دو سو میں سے اگر ایک دو بھی عالم بن گئے تو سب کے لیے کافی ہے، ہاں ایک بھی نہیں بنے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔
غرض فرضِ کفایہ کی یہ شان ہے کہ پوری قوم مل کر فرض کو چھوڑ دے تو پوری قوم گنہگار ہے لیکن اگر ایک فیصد کو عالم بنا دیا، عمل دکھلا دیا تو ساری قوم کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا۔ تو ایک عرض عینی ہے یعنی ہر ہر شخص گنہگار، جو نہیں کرے گا وہی گنہگار ہو گا۔ اس لیے اتنا حصہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے جس سے وہ یہ سمجھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم پر کیا چیزیں فرض ہیں؟ ہم پر کیا ضروریات عائد ہوتی ہیں؟ عورت بھی اور مرد بھی اس کا حقدار ہے۔ اس کا سکھانا فرض ہے خواہ مرد اپنی بچیوں کو سکھلائیں یا مرد کسی ایک عورت کو پڑھا دیں۔ وہ عورت اور عورتوں کو تیار کر دے کہ وہ گھروں میں جا کے یا کسی ایک جگہ مدرسہ قائم کر کے ان بچیوں کو پڑھا دے۔ اس سے زیادہ کوئی قصہ نہیں، ذرا توجہ کی جائے تو یہ معاملہ باآسانی ہو سکتا ہے۔
رہا عالم بنانا، سب کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے اور نہ عورتوں کے لیے۔ قوم میں سے ایک دو بھی بن گئے یا باہر جا کے بن گئے، ہندوستان جا کے بن گئے، پوری قوم سے گناہ ہٹ گیا۔ اس عالم کا فرض ہے وہ اپنی قوم کی اصلاح کرے، جو ان کی دینی ضروریات ہیں انہیں پورا کرے۔ انہیں مسائل بتائے، فتوٰی دے، الجھنوں میں شرعی طور پر ان کی راہنمائی کرے، دل وساوس میں الجھ گئے ہوں تو فکر کا راستہ درست کرے، یہ اس کا فریضہ ہے۔
بہرحال مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی علم و اخلاق کی اتنی حقدار ہیں جتنے آپ حقدار ہیں، جتنا حصہ آپ پر ضروری ہے وہ ان پر بھی ضروری ہے، ان کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ سے مؤاخذہ ہو گا۔ اس واسطے یہ چند جملے میں نے عرض کیے تھے اور آیت یہ تلاوت کی تھی ’’وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِکَۃُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللہَ اصْطَفٰکِ وَطَھَّرَکِ وَاصْطَفٰکِ عَلٰی نِسَآءِ الْعٰلَمِیْنَ‘‘ ملائکہ علیہم السلام جب آئے اور انہوں نے حضرت مریم علیہا السلام سے خطاب کیا۔ یہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ نہایت مقدس اور پاک باز بی بی ہیں۔ حتٰی کہ بعض علماء ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں، ان سے ملائکہ نے خطاب کیا اور کہا:
اے مریم! بشارت حاصل کر، اللہ نے تجھے منتخب کیا، تجھے پاکباز اور مقدس بنایا اور تیرے زمانے میں جتنی عورتیں ہیں ان سب پر تجھے فضیلت دی، بڑائی اور بزرگی دی، جب اللہ نے یہ انعام تجھے دیا اور برتر و برگزیدہ کر دیا تو تیرا کام یہ ہے ’’یٰمَرْیَمُ اقْنُتِیْ لِرَبِّکِ‘‘ اے مریم! اپنے پروردگار کے سامنے عبادت گزار بندی بن کے رہ ’’وَاسْجُدِیْ‘‘ سجدے اختیار کر ’’وَارْکَعِیْ مَعَ الرَّاکِعِیْنَ‘‘ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ رکوع سے مراد نماز ہوتی ہے، جہاں رکوع کا لفظ آتا ہے وہاں نماز کا ذکر ہے، وہاں محض رکوع نہیں بلکہ پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ نماز قائم کرو، عبادتِ خداوندی کو اپنا شعار اور اپنی طبیعت بناؤ
اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ مریم علیہا السلام کتنی بڑی پارسا اور پاک بی بی ہیں، ان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ فرشتوں نے ان سے خطاب کیا۔ یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ یہ بڑی قسمت کی چیز ہے، یہ ایک عورت کو شرف حاصل ہوا۔ اگر حضرت مریم علیہا السلام کو یہ شرف حاصل ہوا، ہماری بہو بیٹیوں کو کیوں نہیں ہو سکتا بشرطیکہ وہ بھی وہی کام کریں جو حضرت مریمؑ نے کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کچھ اور خصوصیات تھیں وہ ان کے ساتھ خاص تھیں لیکن جو بڑائی اور کمال اللہ نے دیا تھا اس کے دروازے اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیے۔ مریم علیہا السلام اگر ولیٔ کامل بن سکتی ہیں تو ہماری عورتیں بھی ولیٔ کامل بن سکتی ہیں۔
نبوت کا بے شک دروازہ بند ہو گیا، نبی اب کوئی نہیں ہو سکتا، ایک ہی نبوت قیامت تک کے لیے کافی ہے، اس نبوت کے طفیل میں بڑے بڑے محدث، امام، مجتہد، اولیائے کاملین اور مجدّد پیدا ہوں گے۔ فیضان قیامت تک اسی نبوت کا کام کرتا رہے گا۔ گویا اتنی کامل نبوت ہے کہ اسے ختم کر کے کسی اور نبوت لانے کی ضرورت نہیں۔ جو مراتبِ نبوت تھے اسی ذات پر ختم کر دیے گئے۔ اب کوئی مرتبہ نبوت کا باقی نہ رہا جس کے لانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے کہ اس پر یہ مرتبہ پورا کیا جائے۔ ایک ہی ذات پر سارے مراتب ختم ہو گئے۔ یہ وہی ذات ہے جس کی روشنی قیامت تک چلتی رہے گی۔ روشنی کو پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہزاروں آئینے پیدا کر دے گا کہ آئینہ آفتاب کے سامنے ہو گا اور عکس اندھیرے مکان میں ڈال دے گا۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا مگر ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس لیے اس نبوت کے نیچے رہ کر جو بڑے سے بڑا کمال مرد کو مل سکتا ہے وہ عورت کو بھی مل سکتا ہے۔
عورتیں مایوس نہ ہوں اور یہ نہ سمجھیں کہ علم وغیرہ تو مردوں کے لیے ہے، ہم صرف گھر میں بیٹھنے کے لیے ہیں۔ گھر میں ہی بیٹھ کر سب کچھ مل سکتا ہے اگر محنت کی جائے اور یہ توجہ کریں۔ اس واسطے میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی اس کے تحت یہ تھوڑی سی تشریح عرض کی۔ خدا کرے ہمارے قلوب قبول کریں اور ہمارے دل مائل ہوں اور ہم حقوق کو پہچانیں۔ ہمیں اگر راعی بنایا گیا ہے تو ہم اپنی رعیت کی خبرگیری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آپ نے پوچھا
ادارہ
عالیجاہ محمد کون تھا؟
سوال: امریکہ کے حوالے سے اکثر عالیجاہ محمد کا نام سننے میں آتا ہے۔ یہ صاحب کون ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں؟ (حافظ عطاء المجید، کبیر والا)
جواب: عالیجاہ محمد سیاہ فام امریکیوں کا ایک لیڈر تھا جس نے اپنے آپ کو مسلم راہنما کی حیثیت سے متعارف کرایا اور سفید فام امریکیوں کے خلاف سیاہ فام طبقہ کی روایتی نفرت کو بھڑکا کر اپنے گرد ایک اچھی خاصی جماعت اکٹھی کر لی، لیکن اس کے عقائد اسلامی نہیں تھے بلکہ اس نے اسلام کا لیبل چسپاں کر کے اپنے خودساختہ عقائد کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ۱۹۳۵ء میں اس نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح پہلے ہلکے پھلکے دعاوی کے ساتھ لوگوں کا مانوس کیا اور پھر ۱۹۵۰ء میں نبوت و رسالت کا کھلا دعوٰی کر دیا۔
اس نے اسلام کے بنیادی احکام کو بدل دیا۔ تمام سفید چیزوں کو حرام قرار دیا۔ نماز کے بارے میں کہا کہ نماز کھڑے ہو کر دعا کرنے کا نام ہے۔ روزے دسمبر میں رکھنے کا حکم دیا۔ حج منسوخ کر کے شکاگو میں اپنے ہیڈکوارٹر پر آنے کو حج کا قائم مقام قرار دیا۔ اور عمومی چندہ کو زکٰوۃ کا نام دے دیا۔
عالیجاہ محمد نے سفید فام لوگوں کے خلاف اپنے پیروکاروں کا یہ ذہن بنایا کہ سفید فام شیطان کی اولاد ہیں اور کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سیاہ فام تھے اور ان کی ساری اولاد سیاہ فام ہے۔
عالیجاہ محمد کے ایک قریبی ساتھی اور دست راست مالکم ایکس نے سب سے پہلے اس کے جھوٹے مذہب سے بغاوت کی اور اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد اختیار کرنے کا اعلان کیا مگر ۱۹۶۵ء میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ مالکم ایکس اب مالکم شہباز شہیدؒ کے نام سے متعارف ہیں اور ان کی یاد میں نیویارک میں ’’مالکم شہباز مسجد‘‘ تعمیر کی گئی ہے جو تبلیغِ اسلام کا معروف مرکز ہے۔
مکہ بازی کے سابق عالمی چیمپئن محمد علی کلے نے بھی ابتداء میں جب قبول اسلام کا اعلان کیا تو وہ عالیجاہ محمد کے پیروکار تھے لیکن جلد ہی مالکم شہباز شہیدؒ کے گروپ میں شامل ہو گئے اور اب وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔
عالیجاہ محمد کی موت کے بعد اس کے فرزند وارث دین محمد بھی باپ کے عقائد سے منحرف ہو چکے ہیں اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ایک بڑے گروپ کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ مالکم شہباز شہیدؒ کا ایک قریبی ساتھی لوئیس فرخان اسلام کے صحیح عقائد سے (معاذ اللہ) منحرف ہو کر اب عالیجاہ محمد کے گمراہ گروپ کی قیادت کر رہا ہے۔
اسلامی نظام میں نمائندگی کا تصور کیا ہے؟
سوال: کیا اسلامی نظام میں حکومت اور عوام کے درمیان نمائندوں کے کسی طبقے کا وجود ہے؟ اور اسلام میں اس کا تصور کیا ہے؟ (حافظ عبید اللہ عامر، گوجرانوالہ)
جواب: کسی مسئلہ پر عوام کی رائے کو صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے نمائندگی کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ غزوۂ حنین کے بعد غنیمت کا مال تقسیم ہوا اور مفتوحین کی طرف سے اپنے قیدی واپس لینے کے لیے ایک وفد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو چونکہ قیدی مجاہدین میں تقسیم ہو چکے تھے اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی واپسی کے لیے مجاہدین کی رضا اور رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مجاہدین کو جمع کیا جن کی تعداد بارہ ہزار کے لگ بھگ تھی، ان سب کے سامنے مسئلہ پیش کر کے ان کی رائے طلب کی، سب نے اجتماعی آواز سے جواب دیا کہ ہمیں قیدیوں کی واپسی بخوشی منظور ہے لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعی جواب پر اکتفاء نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ
انا لا ندری من اذن منکم فی ذٰلک ومن لم یاذن فارجعوا حتٰی یرفع الینا عرفاءکم امرکم۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۱۸)
’’ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں۔ اس لیے تم سب (اپنے خیموں میں) واپس جاؤ حتٰی کہ تمہارے عرفاء تمہارا معاملہ ہمارے سامنے پیش کریں۔‘‘
چنانچہ مجاہدین اپنے خیموں میں چلے گئے اور عرفاء نے ان سے الگ الگ رائے معلوم کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے پہنچایا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی واپسی کا فیصلہ کیا۔
عرفاء ’’عریف‘‘ کی جمع ہے اور عریف عرب معاشرے میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو عوام کے مسائل سرداروں اور حکمرانوں تک پہنچاتے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس طبقہ کو اپنے فیصلہ کی بنیاد بنایا ہے بلکہ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
ان العرافۃ حق ولابد للناس من عرفاء رواہ ابوداؤد (مشکٰوۃ ص ۳۳۱)
’’عرافہ حق ہے اور لوگوں کے لیے عرفاء کا وجود ضروری ہے۔‘‘
اس لیے اسلامی نظام میں حکومت اور عوام کے درمیان ایک ایسے طبقے کے وجود اور اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے جو عام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل اور اجتماعی امور پر ان کی رائے حکومت تک پہنچا سکے۔
جمعیۃ العلماء ہند کب وجود میں آئی؟
سوال: جمعیۃ العلماء ہند کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ (عبد الوحید بٹ، گکھڑ ضلع گوجرانوالہ)
جواب: ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ء کو دہلی میں متحدہ ہندوستان کے سرکردہ علماء کرام کا ایک اجلاس مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی زیرصدارت منعقد ہوا جس میں ’’جمعیۃ العلماء ہند‘‘ کے نام سے علماء کی ایک مستقل جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولانا مفتی کفایت اللہؒ کو جمعیۃ کا پہلا صدر اور مولانا احمد سعیدؒ کو ناظم منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد جمعیۃ کا پہلا اجلاس عام ۲۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو امرتسر میں ہوا جس میں اس کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط کی منظوری دی گئی۔ اور اغراض و مقاصد میں مسلمانانِ ہند کی دینی و سیاسی معاملات میں راہنمائی کے ساتھ ساتھ آزادیٔ وطن کو جمعیۃ کا بنیادی مقصد قرار دیا گیا۔
بنیاد پرست مسلمان کون ہیں؟
سوال: آج کل عام طور پر بعض راہنماؤں کے بیانات میں بنیاد پرست مسلمانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس سے ان کی مراد کون لوگ ہیں؟ (مسعود احمد، لاہور)
جواب: ایک عرصہ سے عالمی اسلام دشمن لابیاں اس منظم کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی عقائد و احکام سے ہٹا کر جدید افکار و نظریات کے ساتھ مفاہمت کے لیے تیار کیا جائے اور مسلمانوں کے اندر ایک ایسی لابی منظم کی جائے جو جدید تعبیر و تشریح اور اجتہاد مطلق کے نام پر قرآن و سنت کے احکام کو نئے اور خودساختہ معنی پہنا سکے۔ مگر راسخ الاعتقاد مسلمانوں اور علماء کے سامنے ان کا بس نہیں چل رہا کیونکہ علماء کرام اس موقف پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں کہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح وہی قابل قبول ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امتِ مسلمہ کے چودہ سو سالہ اجماعی تعامل کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس سے ہٹ کر کی جانے والی کوئی بھی تعبیر سراسر الحاد اور گمراہی ہو گی۔
ان علماء اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کو جو قرآن و سنت کی چودہ سو سالہ اجماعی تعبیر و تشریح پر سختی کے ساتھ قائم ہیں، اسلام دشمن لابیوں کی طرف سے مختلف خطابات و القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے قبل انہیں دقیانوسی اور رجعت پسند کہا جاتا تھا اور اب ان کے لیے ’’بنیاد پرست‘‘ کی نئی اصطلاح ایجاد کی گئی ہے۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’نوادرات ام الکتاب‘‘
حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی دامت برکاتہم کے نوااسے اور علمی جانشین حضرت مولانا شفیق الرحمٰن درخواستی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، وہ ایک اچھے مدرس، با عمل عالم اور بے باک خطیب و واعظ ہیں۔ حضرت درخواستی مدظلہ العالی کی صحبت و تربیت کا رنگ ان پر غالب ہے۔ موصوف ماڈل ٹاؤن خانپور کی جامع مسجد میں روزانہ فجر کے بعد قرآن کریم کا درس دیتے ہیں اور زیرنظر رسالہ ان کے سورۃ الفاتحہ پر چالیس دروس کا مجموعہ ہے جسے جامعہ عبد اللہ بن مسعودؓ خلافتِ راشدہ کالونی خانپور ضلع رحیم یارخان کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ سورۂ فاتحہ کے علوم و معارف اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل کو عام فہم انداز میں ان دروس میں پیش کیا گیا ہے اور علماء و ائمہ کے لیے بالخصوص ان کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ایک سو چالیس صفحات کے اس رسالہ کی قیمت بیس روپے ہے۔
’’خطبات و مواعظ جمعہ‘‘
از: مولانا مشتاق احمد عباسی
صفحات ۵۸۴ قیمت ۱۲۰ روپے
ناشر: ادارہ صدیقیہ، نزد حسین ڈی سلوا بلڈنگز، ویسٹ نشتر روڈ، کراچی۔
خطباء کرام کے لیے ہر جمعہ پر کسی موضوع کی تلاش اور اس کے لیے مناسب مواد کی فراہمی ایک مستقل مسئلہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف زبانوں میں مشاہیر خطباء کرام کے خطبات وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں اور اردو زبان میں بھی خطبات کے بعض مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ زیر نظر ’’مجموعہ خطبات‘‘ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جسے ہمارے فاضل دوست مولانا حافظ مشتاق احمد عباسی نے مرتب کیا ہے اور ہجری سال کے بارہ مہینوں کی مناسبت سے ہر ماہ کے لیے پانچ خطبات مرتب کر دیے ہیں۔ اندازِ بیان عام فہم ہے اور موضوعات کے مطابق معلومات کا معتمد بہ ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے۔ خطباء کرام کے لیے یہ مجموعہ ایک اچھا تحفہ ہے جو ان کے لیے موضوع اور مواد کی تلاش میں خاصی آسانی پیدا کر دے گا۔
’’احسان الباری لفہم البخاری‘‘
از: شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
صفحات ۱۳۲ قیمت ۱۸ روپے۔
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں بخاری شریف کے آغاز میں حجیت حدیث اور کتاب الایمان کے بعض علمی مباحث دورۂ حدیث کے طلباء کو املا کراتے ہیں۔ حضرت الشیخ مدظلہ کے فرزند مولانا رشید الحق عابد مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم نے انہیں مرتب کیا ہے اور مکتبہ حنفیہ اردو بازار گوجرانوالہ نے علماء اور طلبہ کے عمومی استفادہ کے لیے یہ مجموعہ شائع کر دیا ہے۔
شرعی سزاؤں کا فلسفہ
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
اعلم ان من المعاصی ما شرع اللہ فیہ الحد و ذلک کل معصیۃ جمعۃ وجوھا من المفسدۃ بان کانت فسادا فی الارض واقتضا با علی طمانینۃ المسلمین و کانت لھا داعیۃ فی نفوس بنی اٰدم لا تزال تہیج فیھا ولھا ضراوۃ لا یستطیعون الا قلاع منھا بعد ان اشربت قلوبھم لھا وکان فیہ ضرر لا یستطیع المظلوم دفعہ عن نفسہ فی کثیر من الاحیان و کان کثیر الوقوع فیما بین الناس فمثل ھٰذہ المعاصی لا یکفی فیھا الترھیب بعذاب الآخرۃ بل لابد من اقامۃ ملامۃ شدیدۃ وایلام لیکون بین اعینھم ذلک فیردعھم عما یریدونہ۔ (حجۃ اللہ البالغۃ مبحث فی الحدود)
ترجمہ: ’’جان لو کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں اللہ تعالٰی نے حد (دنیاوی سزا) مقرر فرمائی ہے۔ اس لیے کہ ہر گناہ فساد کے کچھ اسباب پر مشتمل ہوتا ہے جس سے زمین میں خرابی ہوتی ہے اور مسلمانوں کا امن و سکون غارت ہوتا ہے۔ اس گناہ کی خواہش انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے جو برابر بڑھتی رہتی ہے اور دلوں میں خواہش کے جڑ پکڑ جانے کے بعد وہ اس بری عادت سے نکلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور اس میں ایسا ضرر ہے جسے مظلوم اپنے آپ سے دور رکھنے کی اکثر اوقات طاقت نہیں پاتا اور یہ صورت بہت زیادہ لوگوں میں وقوع پذیر رہتی ہے۔ پس اس قسم کے گناہوں میں صرف آخرت کے عذاب سے ڈرانا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ شدید قسم کی سزا اور ملامت قائم کی جائے تاکہ وہ (سزا) ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور انہیں ان کے (برے) ارادوں سے باز رکھ سکے۔‘‘
کمیونزم نہیں، اسلام
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
نام نہاد کمیونزم میں جس قدر مسکین نوازی ہے اس سے کہیں زیادہ امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالٰی کے فلسفے میں ہے، اور اس میں مزدور اور کاشتکار کے حقوق کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد خدا کے صحیح اور صاف تصور پر ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک کارکن اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس زندہ تصور کے ساتھ گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالٰی اسے دیکھ رہا ہے۔وہ یہ تصور بھی ایک زندہ اور پائیدار شکل میں اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اگر اس نے کم تولا یا کسی کے حق کو ناجائز طور پر پاؤں تلے روندا تو دنیا میں بھی سزا پائے گا اور مرنے کے بعد بھی اسے اللہ تعالٰی کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہو گی۔امام ولی اللہ رحمہ اللہ تعالٰی کی حکمت اسے یہ بھی سکھاتی ہے کہ قرآنِ حکیم پر عمل کرنے والے کارکن کو اللہ تعالٰی کے سوا کسی سے اپنے عمل کا بدلہ لینا ضروری نہیں۔
انسان بے شک اس لیے پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں قرآن حکیم کی حکومت بین الاقوامی درجہ پر چلائے، لیکن وہ اس حکومت کے ذریعے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ قرآن حکیم کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کی حکومتیں بے نظیر ثابت ہوئیں اور آج تک دنیا ان کی مثال پیدا نہیں کر سکی۔ اب اس دور میں بھی امیر المومنین سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالٰی اور ان کے ساتھیوں نے انہی اصولوں پر اس نمونے کی حکومت پیدا کر کے ایک دفعہ پھر دکھا دی اور ثابت کر دیا کہ اس قسم کی حکومت پیدا کرنا ہر زمانے میں ممکن ہے۔ قرآن حکیم کے ماننے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت اور ذمہ داری ہے۔
(عنوانِ انقلاب ص ۵۹)
فروری ۱۹۹۰ء
عالمِ اسلام میں جہاد کی نئی لہر
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
جہاد افغانستان کے منطقی اثرات رفتہ رفتہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ نہ صرف مشرقی یورپ نے روس کی بالادستی کا طوق گلے سے اتار پھینکا ہے بلکہ وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی اپنی آزادی اور تشخص کی بحالی کے لیے قربانی اور جدوجہد کی شاہراہ پر گامزن ہو چکی ہیں اور فلسطین، کشمیر اور آذربائیجان کے حریت پسند مسلمان جذبۂ جہاد سے سرشار ہو کر ظلم و استبداد کی قوتوں کے خلاف صف آرا ہیں۔ جہاد کے اسی جذبہ سے کفر کی قوتیں خائف تھیں اور اسے مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے استعماری طاقتیں گزشتہ دو سو برس سے فکری، سیاسی اور تہذیبی سازشوں کے جال بن رہی تھیں لیکن اسلام کی زندہ و متحرک قوت اور جہاد کے ناقابل تسخیر جذبے نے افغانستان کی سنگلاخ وادیوں میں ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اس سازش کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ فلسطین میں انتفاضہ کی تحریک فلسطینی مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ کے وجود کا احساس دلا رہی ہے، کشمیری حریت پسندوں کی مسلح جدوجہد نے دنیا کو بھولا بسرا مسئلہ کشمیر پھر سے یاد دلا دیا ہے اور آذربائیجان میں روسی ٹینکوں کا نشانہ بننے والے غیور مسلمانوں نے اپنے خون کے ساتھ تاریخ کی یہ حقیقت ایک بار رقم کر دی ہے کہ مسلمان کو اس غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے مغلوب تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے زیادہ دیر تک قابو میں رکھنا کسی بڑی سے بڑی طاقت کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔
حریت اور غیرت کے یہ شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں مگر استبداد و استعمار کے علم بردار ان شعلوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا دامن بچانے کی فکر میں جہاد کی اس نئی عالمگیر لہر کے سرچشمہ ’’جہادِ افغانستان‘‘ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور واشنگٹن، ماسکو اور اسلام آباد جہادِ افغانستان کے منطقی اور نظریاتی نتائج کو روکنے کے لیے گٹھ جوڑ کر چکے ہیں لیکن یہ ان کی بھول اور تاریخ کے عمل سے بے خبری ہے۔ جہاد افغانستان کے منطقی اور نظریاتی اثرات پوری دنیا کو حصار میں لے رہے ہیں تو کابل کو مصنوعی سہاروں کے ساتھ ’’اثر پروف‘‘ رکھنا آخر کب تک ممکن ہوگا؟ماسکو، واشنگٹن اور اسلام آباد کو اس حقیقت کا بالآخر ادراک کرنا ہوگا کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا۔
سیرتِ نبویؐ کی جامعیت
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی تشریف لائے ہیں ہم ان سب کو سچا مانتے ہیں اور ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور ایسا کرنا ہمارے فریضہ اور عقیدہ میں داخل ہے ’’لا نفرق بین احد من رسلہ‘‘۔ مگر اس ایمانی اشتراک کے باوجود بھی ان میں سے ہر ایک میں کچھ ایسی نمایاں خصوصیات اور کچھ جداگانہ کمالات و فضائل ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر ہرگز کوئی چارۂ کار نہیں ہے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء و رسل علیہم السلام تشریف لائے ہیں تو ان سب کی دعوت کسی خاص خاندان اور کسی خاص قوم سے مخصوص رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو اپنی دعوت کو صرف اپنی ہی قوم تک محدود رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو فقط عاد کو خطاب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو محض قوم ثمود کی فکر لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پیغمبر تھے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور حضرت عیسٰی علیہ السلام تو بس بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کی تلاش اور سراغ میں نکلے تھے۔ جب غیروں نے ان کے روحانی کمالات سے استفادہ کرنے کی اپیل کی تو انہوں نے جواب میں کہا ’’لڑکوں کی روتی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں‘‘ (انجیل متی باب ۱۵ آیت ۲۶)
یہی وجہ تھی کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی قوم سے باہر نظر نہیں ڈالی لیکن جب رحمتِ خداوندی کی وہ عالمگیر گھٹا جو فاران کی چوٹیوں سے اٹھی تھی جس سے انسانیت و شرافت، دیانت و امانت، عدل و انصاف اور تقوٰی و ورع کی مرجھائی ہوئی کھیتیاں پھر سے سرسبز و شاداب ہو کر لہلہا اٹھیں، وہ قوم و جماعت، ملک و زمین، مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور بر و بحر کی تمام قیدوں اور پابندیوں سے بالکل آزاد تھی۔ وہ بلا امتیاز وطن و ملت، بلا تفریق نسل و خاندان، بدوں تمیز رنگ و خون، بغیر لحاظ سیاہ و سپید اور بے اعتبار حسب و نسب تا قیامت پوری نسل انسانی کے لیے رحمتِ مہداۃ بن کر نمودار ہوئی اور رب ذوالاحسان نے خود آپ ہی کی زبان فیض رساں سے یہ اعلان کروا دیا کہ
قُلْ یَآ اَیُّھَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللہِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا (پ ۹ ۔ اعراف ۔ ع ۱۹)
’’آپ کہہ دیجیئے کہ اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔‘‘
وہ ابرِ کرم اٹھا تو فاران کی چوٹیوں سے مگر سب روئے زمین پر پھول برساتا اور مژدۂ جانفزا سناتا ہوا چلا گیا اور پوری دھرتی کے چپہ چپہ پر خوب کھلکھلا کر برسا۔ دشت و صحرا نے اس سے آسودگی حاصل کی، بحر و بر اس سے سیراب ہوئے، چمنستانوں نے اس سے رونق پائی، اور ویرانوں کو اس کی فیض پاشی نے لعل و گوہر سے معمور کر دیا۔ اہلِ عرب اس سے مستفید ہوئے، باشندگان عجم نے اس سے اکتسابِ فیض کیا، یورپ نے اس کی خوشہ چینی کی اور ایشیا اس کا گرویدہ بنا۔ دنیا کے تمام گمراہوں کو وادیٔ ضلالت سے نکالنے کی اس نے راہنمائی کی اور آوارگانِ دشت غوایت کی رہبری کی اور نسل انسانی کے سب مایوس مریضوں اور ہر قسم کے ناامید بیماروں کو زود اثر تریاق اور نسخۂ شفا بخشا ؎
اتر کر جراء سے سوئے قوم آیا
اور ایک نسخۂ کیمیا ساتھ لایا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت صرف نسلِ انسانی ہی کے لیے نہیں بلکہ جنّات بھی اس امر کے مکلّف اور پابند ہیں کہ آپؐ کی نبوت و رسالت کا اقرار کر کے آپؐ کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نجاتِ اخروی تلاش کریں۔ ثقلین (انس و جن) کا مکلف ہونا نیز جنات کا قرآن کریم کو غور و فکر سے سن کر اس پر ایمان لانا اور پھر جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کرنا قرآن مجید میں مصرّح ہے اور عالمین کے مفہوم میں جنات بھی شامل ہیں اور قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپؐ کو تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے ‘‘لِیَکُوْنَ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا‘‘۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
ارسلت الی الاحمر والاسود قال مجاھد الانس والجن۔ (مستدرک ج ۲ ص ۴۲۴ قال الحاکمؒ والذھبیؒ علی شرطھما)
’’مجھے سرخ اور سیاہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ سرخ سے انسان اور سیاہ سے جن مراد ہیں۔‘‘
جو مکارمِ اخلاق آپؐ کو خالقِ کونین کی طرف سے مرحمت ہوئے تھے اور جن کی تکمیل کے لیے آپؐ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ مکلّف مخلوق کی فطرت کے جملہ مقتضیات کے عین مطابق تھے اور جن کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ ان کے ذریعے روحانی مریضوں کو ان کے بستروں سے اٹھا دیا جائے بلکہ یہ بھی تھا کہ اٹھنے والوں کو چلایا جائے اور چلنے والوں کو بسرعت دوڑایا جائے اور دوڑنے والوں کو روحانی کمال اور اخلاقی معراج کی غایۃ قصوٰی تک اور سعادتِ دنیوی ہی نہیں بلکہ سعادتِ دارین کی سدرۃ المنتہٰی تک پہنچایا جائے۔ اور ان کی نعمت فقط مریضوں کے لیے قوت بخش اور صحت افزاء نہ ہو بلکہ وہ تمام مکلف مخلوق کی اصل فطری اور روحانی لذیذ غذا بھی ہو۔ اور آپؐ کے مکارمِ اخلاق اور اسوۂ حسنہ نے وہ تمام ممکن اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ خلقِ عظیم کی بلند اور دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا آسان اور سہل ہو گیا ہے۔ آپؐ کی بعثت کے اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا جیسا کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ
انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق و فی روایۃ مکارم الاخلاق (قال الشیخ حدیث صحیح ۔ السراج المنیر ج ۲ ص ۲۷)
’’مجھے تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں نیک خصلتوں اور مکارمِ اخلاق کی تکمیل کروں۔‘‘
اور یہ ناقابلِ تردید حقیقت ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام خاص خاص جماعتوں اور مخصوص قوموں کے لیے مصلح اور پیغمبر تھے اسی طرح ان کی روحانیت اور اخلاقی آئینے بھی خصوصی صفات اور اصناف کے مظہر تھے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام مجرم اور نافرمان قوم کی نجات کے لیے باوجود قوم کی ایذا رسانی کے سعی بلیغ کی زندہ یادگار تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اخلاص و قربانی کی مجسم مثال تھے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے اور عزیز ترین لختِ جگر کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضاجوئی کے لیے اپنی طرف سے ذبح کر ہی ڈالا اور اس کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمزوری نہ دکھائی، جس کی ایک ادنٰی اور معمولی سی برائے نام نقل آج بھی ہر صاحبِ استطاعت مسلمان اتارتا اور ’’سُنَّۃَ اَبِیْکُمْ اِبْرَاھِیْم‘‘ کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ ؎
تیری ذبح ذبحِ عظیم کی ہو مثیل کیوں کر خلوص میں
نہ خلیلؑ کا سا ہے دل تیرا نہ ذبیحؑ کا سا گلا تیرا
حضرت ایوب علیہ السلام صبر و رضا کے پیکر تھے، مصائب و آلام کے بے پناہ سیلاب بہہ گئے مگر وہ مضبوط پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ثابت رہے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کی زندگی جرأت حق کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی کہ فرعون جیسے جابر اور مطلق العنان بادشاہ کے دربار میں ساون کے بادلوں کی طرح گرج اور صاعقہ آسمانی کی طرح کڑک کر تہلکہ ڈال دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر آزما حیات یادگارِ دہر تھی کہ اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھ سے پیارے یوسفؑ کے سلسلہ میں اذیت اور دکھ اٹھا کر ’’فَصَبْر جَمِیْل‘‘ فرما کر خاموش ہو گئے اور اندر ہی اندر آنسوؤں کے طوفان موجیں مارتے ہوئے ساحل امید سے ٹکراتے رہے اور ناامیدی کو قریب نہیں آنے دیا کہ
نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام کی عفتِ مآب زندگی پاکدامن نوجوان کے لیے باعث صد افتخار ہے کہ انہوں نے ’’امراۃ عزیز‘‘ کی تمام مکّاریوں اور حیلہ جوئیوں کی استخواں شکن زنجیروں کی ایک ایک کڑی کو معاذ اللہ فرماتے ہوئے پاش پاش کر دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی شاہانہ زندگی ان سب سے نرالی تھی کہ قبائے سلطنت اور عبائے خلافت اوڑھ کر مخلوقِ خدا کے سامنے ظہور پذیر ہوئے اور اس طریقہ سے عدل و انصاف کے مطابق ان کی خدمت کا عمدہ فریضہ انجام دیا۔ حضرت عیسٰی علیہ السلام توکل و قناعت، زہد و خودفراموشی کی ایک پوری کائنات تھے کہ زندگی بھر سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی اور فرمایا ’’اے لوگو! یہ کیوں سوچتے ہو کہ کیا کھاؤ گے؟ فضا کی چڑیوں کے لیے کاشتکاری کون کرتا ہے؟ اور ان کے منہ میں خوراک کون ڈالتا ہے؟ اے لوگو! تمہیں اس کی کیا فکر ہے اور تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو اتنی دیدہ زیب پوشاک اور خوبصورت لباس کون پہناتا ہے؟‘‘
یہ تمام بزرگ اور مقدس ہستیاں اپنے اپنے وقت پر تشریف لائیں اور بغیر حضرت مسیح علیہ السلام سب دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن جب قصرِ نبوت اور ایوانِ رسالت کی آخری اینٹ کا ظہور ہوا جس کی انتظار میں دہر کہن سال نے ہزاروں برس صرف کر دیے تھے، آسمان کے ستارے اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، ان کے استقبال کے لیے لیل و نہار بے شمار کروٹیں بدلتے رہے، ان کی آمد سے محض کسرٰی کے محل کے چودہ کنگرے ہی نہیں بلکہ رسم عرب، شان عجم، شوکت روم، فلسفہ یونان اور اوجِ چین کے قصرہائے فلک بوس گر کر آن واحد میں پیوند زمین ہو گئے تو پورے کرۂ ارض کے لیے ایک عالم گیر سعادت اور ایک ہمہ گیر رحمت لے کر آئی۔ آپؐ کا وجود مقدس روحانیت کے تمام اصناف کی ایک خوشنما کائنات، اخلاق حسنہ کی ایک دلآویز جاذبیت اور رنگ برنگ گل ہائے اخلاق کا ایک پورا چمنستان تھا۔ امتِ مرحومہ کے لیے حضرت نوحؐ کی دلسوزی، حضرت ابراہیمؐ کی خلّت، حضرت ایوبؐ کا صبر، حضرت داؤدؐ کی مناجات، حضرت موسٰیؐ کی جرأت، حضرت ہارونؐ کا تحمل، حضرت سلیمانؐ کی سلطنت، حضرت یعقوبؐ کی آزمائش، حضرت یوسفؐ کی عفت، حضرت زکریاؐ اور حضرت یحیٰیؐ کی تقرب الٰہی کے لیے گریہ و زاری، اور حضرت مسیحؐ کا توکل، یہ تمام منتشر اوصاف آپؐ کے وجود مسعود میں سمٹ کر جمع اور یکجا ہو چکے تھے۔ سچ ہے کہ ؎
حسنِ یوسفؐ دمِ عیسٰیؐ یدِ بیضاداری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری
غرض کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کی زندگی خاص خاص اوصاف میں نمونہ اور اسوہ تھی مگر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و ارفع زندگی تمام اوصاف و اصناف میں ایک جامع زندگی ہے۔ آپؐ کی سیرت مکمل اور آپؐ کا اسوۂ حسنہ ایک کامل ضابطۂ حیات اور دستور ہے۔ اس کے بعد اصولی طور پر کسی اور چیز کی سرے سے کوئی حاجت ہی باقی نہیں رہ جاتی اور نہ کسی اور نظام و قانون کی ضرورت ہی محسوس ہو سکتی ہے ؎
سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر
اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ مرے اس دعا کے بعد
- اگر آپ بادشاہ اور سربراہِ مملکت ہیں تو شاہِ عربؐ اور فرمانروائے عالمؐ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔
- اگر آپ فقیر و محتاج ہیں تو کمبلی والےؐ کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے جنہوں نے کبھی دقل (ردی قسم کی کھجوریں) بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور جن کے چولہے میں بسا اوقات دو دو ماہ تک آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔
- اگر آپؐ سپہ سالار اور فاتح ملک ہیں تو بدر و حنین کے سپہ سالار اور فاتح مکہ کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین سبق ہے جس نے عفو و کرم کے دریا بہا دیئے تھے اور ’’لا تثریب علیکم الیوم‘‘ کا خوش آئند اعلان فرما کر تمام مجرموں کو آنِ واحد میں معافی کا پروانہ دے کر بخش دیا تھا۔
- اگر آپ قیدی ہیں تو شعبِ ابی طالب کے زندانی کی حیات آپ کے لیے درسِ عبرت ہے۔
- اگر آپ تارکِ دنیا ہیں تو غارِ حرا کے گوشہ نشین کی خلوت آپ کے لیے قابل تقلید عمل ہے۔
- اگر آپ چرواہے ہیں تو مقام اجیاد میں آپؐ کو چند قراریط (ٹکوں) پر اہل مکہ کی بکریاں چراتے دیکھ کر تسکینِ قلب حاصل کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ معمار ہیں تو مسجد نبوی کے معمار کو دیکھ کر ان کی اقتداء کر کے خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ مزدور ہیں تو خندق کے موقع پر اس بزرگ ہستی کو پھاوڑا لے کر مزدوروں کی صف میں دیکھ کر اور مسجد نبویؐ کے لیے بھاری بھر کم وزنی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھ کر قلبی راحت حاصل کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ مجرّد ہیں تو اس پچیس سالہ نوجوان کی پاکدامن اور عفت مآب زندگی کی پیروی کر کے سرورِ قلب حاصل کر سکتے ہیں جس کو کبھی کسی بدترین دشمن نے بھی داغدار نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی جرأت کی ہے۔
- اگر آپ عیال دار ہیں تو آپ متعدد ازواج مطہرات کے شوہر کو ’’انا خیرکم لاھلی‘‘ فرماتے ہوئے سن کر جذبۂ اتباع پیدا کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ یتیم ہیں تو حضرت آمنہ ؑ کے لعل کو یتیمانہ زندگی بسر کرتے دیکھ کر آپؑ کی پیروی اور تاسّی کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ ماں باپ کے اکیلے بیٹے ہیں اور بہنوں اور بھائیوں کے تعاون و تناصر سے محروم ہیں تو حضرت عبد اللہ ؑ کے اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر اشک شوئی کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ باپ ہیں تو حضرت زینبؓ، رقیہؓ، ام کلثومؓ، قاسمؓ اور ابراہیمؓ (وغیرہ) کے شفیق و مہربان باپ کو ملاحظہ کر کے پدرانہ شفقت پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔
- اگر آپ تاجر ہیں تو حضرت خدیجہؓ کے تجارتی کاروبار میں آپؐ کو دیانت دارانہ سعی کرتے ہوئے معائنہ کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ عابد شب خیز ہیں تو اسوۂ حسنہ کے مالک متورّم قدموں کو دیکھ کر اور ’’افلا اکون عبدًا شکورًا‘‘ فرماتے ہوئے آپؐ کی اطاعت کو ذریعۂ تقربِ خداوندی اختیار کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ مسافر ہیں تو خیبر و تبوک کے مسافر کے حالات پڑھ کر طمانیتِ قلب کا وافر سامان مہیا کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ امام اور قاضی ہیں تو مسجد نبوی کے بلند رتبہ امام اور فصل خصومات کے بے باک اور منصف مدنی جج کو بلاامتیاز قریب و بعید اور بغیر تفریق قوی و ضعیف فیصلہ صادر فرماتے ہوئے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
- اور اگر آپ قوم کے خطیب ہیں تو خطیبِ اعظم کو منبر پر جلوہ افروز ہو کر بلیغ اور مؤثر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اور غافل قوم کو ’’انی انا نذیر العربان‘‘ فرما کر بیدار کرتے ہوئے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
الغرض زندگی کا کوئی قابل قدر اور مستحق توجہ پہلو اور گوشہ ایسا باقی نہیں رہ جاتا جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم اور قابل اقتداء زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، عمدہ ترین اسوہ اور اعلیٰ ترین معیار نہ بنتی ہو۔ پس اس وجودِ قدسی پر لاکھوں بلکہ کروڑوں درود و سلام جس کے وجود مسعود میں ہماری زندگی کے تمام پہلو سمٹ کر آجاتے ہیں اور ہماری روح کا ایک ایک گوشہ عقیدت و اخلاص کے جوش سے معمور ہو جاتا ہے جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے لعل و گوہر کا جو پائیدار خزانہ تمام ارض و سماء اور بحر و بر چھان ڈالنے کے بعد بھی کسی قسمت پر جمع نہیں ہو سکتا تھا وہ انمول خزانہ امت مرحومہ کو اپنے پیارے نبیؐ کے اسوۂ حسنہ، اپنے برگزیدہ رسولؐ کی سنتِ صحیحہ اور اپنے مقبول رسولؐ کے معدنِ حدیث کی ایک ہی کان اور معدن سے فراہم ہو گیا ہے، اور قرآن کریم کے بعد ہماری تمام بیماریوں کا مداوا حدیث پاک میں علیٰ وجہ الاتم موجود ہے ؎
اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن
پس حدیث مصطفٰی برجاں مسلّم داستن
عصمتِ انبیاءؑ کے بارے میں اہلِ اسلام کا عقیدہ
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
یہ ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا مقرب جبھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کی موافق مرضی ہو۔ جو لوگ مخالف مزاج ہوتے ہیں قربت و منزلت ان کو میسر نہیں آسکتی، چنانچہ طاہر ہے۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یوسفِ ثانی اور حسن میں لاثانی ہو، پر اس کی ایک آنکھ مثلاً کانی ہو تو اس ایک آنکھ کا نقصان تمام چہرہ کو بدنما اور نازیبا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک بات بھی کسی میں دوسروں کے مخالف مزاج ہو تو ان کی اور خوبیاں بھی ہوئی نہ ہوئی برابر ہو جائیں گی۔ غرض ایک عیب بھی کسی میں ہوتا ہے تو پھر محبوبیت اور موافقت طبیعت و رضا متصور نہیں جو امید تقرب ہو، اس لیے یہ بھی ضرور ہے کہ انبیاء اور مرسل سراپا اطاعت ہوں اور ایک بات بھی ان میں خلافِ مرضی خداوندی نہ ہو۔
اسی وجہ سے ہم انبیاء ؑ کو معصوم کہتے ہیں اور اس کہنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان میں گناہِ خداوندی کا مادہ اور سامان ہی نہیں کیونکہ ان میں جب ان میں کوئی صفت بری نہیں تو پھر ان سے برے افعال کا صادر ہونا بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ افعال اختیاری تابع صفات ہوتے ہیں۔ اگر سخاوت ہوتی ہے تو داد دوہش کی نوبت آتی ہے، اور اگر بخل ہوتا ہے تو کوڑی کوڑی جمع کی جاتی ہے۔ شجاعت میں معرکہ آرائی اور بزدلی میں پسپائی ظہور میں آتی ہے۔ ہاں یہ بات ممکن ہے کہ بوجہ سہو یا غلط فہمی، جو گاہ بگاہ بڑے بڑے عاقلوں کو بھی پیش آجاتی ہے اور سوائے خداوند علیم و خبیر اور کوئی اس سے منزہ نہیں، کسی مخالف مرضی کام کو موافق مرضی اور موافق مرضی کو مخالف مرضی سمجھ جائیں، اور اس وجہ سے بظاہر خلاف مرضی کام ہو جائے تو ہو جائے (مثلًا اپنا مخدوم اپنے برابر بٹھلائے اور یہ بوجہ ادب برابر نہ بیٹھے) یا بوجہ عظمت و محبت مطاع ہی مخالفت کی نوبت آجائے گی، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ گناہ کے لیے یہ ضرور ہے کہ عمدًا مخالفت کی جائے۔ بھول چوک کو لغزش کہتے ہیں گناہ نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ موقعہ عذر میں یہ کہا کرتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا یا میں سمجھا نہ تھا۔ اگر بھول چوک بھی گناہ ہی ہوا کرتا تو یہ عذر اور الٹا اقرار خطا ہوا کرتا عذر نہ ہوا کرتا۔
جب یہ بات واضح ہو گئی کہ افعال تابع صفات ہیں تو اب دو باتیں قابلِ لحاظ باقی رہیں۔ ایک اخلاق یعنی صفات اصلیہ، دوسرے عقل و فہم۔ اخلاق کی ضرورت تو یہیں سے ظاہر ہے کہ افعال جن کا کرنا نہ کرنا عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری میں مطلوب ہوتا ہے، ان کا بھلا برا ہونا اخلاق کی بھلائی برائی پر موقوف ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ اصل میں بھلی اور بری اخلاق و صفات ہی ہوتی ہیں۔ اور عقل و فہم کی ضرورت تو اس لیے ہے کہ اخلاق کے مرتبے میں موقع بے موقع دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ افعال میں بوجہ بے موقع ہو جانے کے کوئی خرابی اوپر سے نہ آجائے۔ دیکھیے سخاوت اچھی چیز ہے لیکن موقع میں صرف ہونا پھر بھی شرط ہے، اگر مساکین اور مستحقین کو دیا جائے تو فبہا ورنہ، رنڈیوں اور بھڑووں کو دینا یا شراب خواروں اور بھنگ نوشوں کو عطا کرنا کون نہیں جانتا کہ اور برائیوں کا سامان ہے، وجہ اس کی بجز اس کے اور کیا ہے کہ بے موقع صرف ہوا۔
بالجملہ افعال ہر چند تابع صفات ہیں لیکن موقع بے موقع کا پہچاننا بجز عقلِ سلیم و فہمِ مستقیم ہرگز متصور نہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ انبیاء ؑ میں عقل کامل اور اخلاقِ حمیدہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب اخلاقِ حمیدہ ہوں گے تو محبت بھی ضرور ہو گی کیونکہ خلقِ حسن کی بنا محبت ہی ہے، اور جب موقع اور محل کا لحاظ ہے اور عقلِ کامل موجود ہے تو پھر خدا سے بڑھ کر اور کونسا موقع سزاوار محبت ہو گا۔ مگر خدا کے ساتھ محبت ہو گی تو پھر عزمِ اطاعت و فرمانبرداری بھی ضرور ہو گا جس کا انجام یہی نکلے گا کہ ارادۂ نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں اور ظاہر ہے کہ اسی کو معصومیت کہتے ہیں۔
(انتخاب: حافظ محمد عمار خان ناصر)
علومِ قرآنی پر ایک اجمالی نظر
مولانا سراج نعمانی
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت فضائل و خصوصیات قرآن مجید بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک جامع آیت کریمہ یہ بھی ہے، فرماتے ہیں:
یٰآ اَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْکُمْ مَّوْعِظَۃُ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَآءُ لِّمَا فِی الصُّدُوْر وَھْدًی وَّرَحْمَۃُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ۔
’’اے لوگو تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے اور شفا ہے جو کچھ دلوں میں ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے واسطے ایمان والوں کے۔‘‘
گویا قرآن مجید کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ پروردگار کی طرف سے نصیحت ہے، قلبی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید نزول سے قبل لوح محفوظ پر تھا، وہاں سے لیلۃ القدر میں آسمانِ دنیا پر نازل کیا گیا اور وہاں سے پھر وقتاً فوقتاً تئیس سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ علی الترتیب ان کیفیات کا مطالعہ کیجئے۔
نزولِ قرآن
بَلْ ھُوَ قُرْاٰنُ مَّجِیْد۔ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظ (البروج پ ۳۰)
’’بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔‘‘
شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْہِ الْقُرْاٰن (البقرہ پ ۲)
’’مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا ہے قرآن مجید۔‘‘
اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَۃِ الْقَدْر (القدر پ ۳۰)
’’بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآن لیلۃ القدر میں۔‘‘
اِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَق (العلق پ ۳۰)
’’پڑھ اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔‘‘
یہ قرآن مجید نزول کے اعتبار سے دو ادوار میں مکمل ہوا۔ پہلا دور مکی کہلاتا ہے جس میں اصول و کلیاتِ دین اور اقوامِ سابقہ کے واقعات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا دور مدنی کہلاتا ہے جس میں عموماً مسلمانوں کو خطاب کر کے عبادات و معاملات سے متعلق احکام تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ نزولِ قرآن کو وحی کہا جاتا ہے جو دو قسم کی ہوتی ہے۔ وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ نزولِ وحی کے طریقے قرآن مجید میں مندرجہ ذیل بیان کیے گئے ہیں۔
وَ مَا کَانَ لِبَشَرٍ اَن یُّکَلِّمَہُ اللہُ اِلَّا وَحْیًا اَوْ مِن وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا فَیُوْحِیَ بِاِذْنِہٖ مَا یَشَآءُ اِنّہٗ عَلِیُّْ حَکِیْم (الشورٰی پ ۲۵)
’’اور نہیں طاقت کسی شخص کی کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وحی سے یا پردے کی آڑ سے یا بھیجے فرشتہ پیغام لانے والا، پس جی میں ڈالتا ہے اس کے حکم سے جو چاہتا ہے، تحقیق وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔‘‘
تدوینِ قرآن
قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین دو طریقوں سے کی گئی۔ صدری حفاظت میں حفظ کے ذریعے حفاظت کی گئی، اور تحریری حفاظت میں کتابت کی صورت میں حفاظت کی گئی۔ حفظ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہے کہ
بَلْ ھُوَ اٰیٰتُْ بَیِّنٰتُْ فِیْ صُدُوْرِ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ، وَمَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَا اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ (العنکبوت پ ۲۱)
’’بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں کہ دیے گئے ہیں علم، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا سوائے ظالموں کے۔‘‘
اس لیے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ فرمایا اور پھر صحابہ کرامؓ کو حفظ کرایا۔
اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَہٗ وَقُرْاٰنَہٗ (القیامۃ پ ۲۹)
’’بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا (تیرے دل میں) اور پڑھنا اس کا (تیری زبان سے)۔‘‘
سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسٰی (الاعلٰی پ ۳۰)
’’عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔‘‘
اس کے بعد حضورؐ نے خدا کے حکم سے یہ قرآن مجید صحابہ کرامؓ تک پہنچایا۔
یَآ اَیُّھَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْکَ (المائدہ پ ۶)
’’اے پیغمبر پہنچا دے جو کچھ کہ اتارا گیا ہے آپ کی طرف۔‘‘
اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ (پ ۲۱)
’’پڑھ جو کچھ وحی کی جاتی ہے تیری طرف کتاب میں سے۔‘‘
ان احکام پر حضورؐ کے عمل کو نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہے:
یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا (پ ۲)
’’پڑھتا ہے تم پر آیتیں ہماری۔‘‘
قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے آداب بھی خود خداوند نے مقرر فرمائے۔
وَاِذَا قَرَأتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْم (النحل پ ۱۴)
’’پھر جب تو پڑھے قرآن تو پناہ مانگ اللہ کی شیطان مردود سے۔‘‘
وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَہٗ وَاَنْصِتُوْا۔ (الاعراف پ ۹)
’’اور جب پڑھا جائے قرآن تو سنو اسے اور چپ رہو۔‘‘
یہ ادب بھی بتایا کہ پڑھتے ہوئے حلاوت، خوش الحانی اور رقت سے پڑھا جائے تاکہ کوئی دوسرا کلام اس کے مقابلے میں ایسی لذت پیدا نہ کرے اور آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے۔
وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِیْلًا (المزمل پ ۲۹)
شاید اسی لیے سورتوں میں بھی تقسیم کیا گیا کہ حفظ میں آسانی ہو، اور تدریجًا تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تاکہ صحابہ کرامؓ آسانی سے یاد کر سکیں۔
وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰہُ لِتَقْرَءَہٗ عَلَی النَّاسِ عَلٰی مُکْثٍ وَّنَزَّلْنَاہُ تَنْزِیْلًا (بنی اسرائیل پ ۱۵)
’’اور قرآن، جدا جدا کیا ہم نے اس کو، تاکہ پڑھے تو اسے لوگوں پر آہستگی سے، اور اتارا ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارنا۔‘‘
عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا، انہوں نے اسے بخوبی یاد کیا۔ اسی حفظ کے لیے ترغیب دیتے ہوئے نماز میں بھی قراءت فرض کی گئی تاکہ حفظ کا جذبہ پیدا ہو۔
اَقِمِ الصّلٰوۃَ لِدُلُوْکِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ (بنی اسرائیل پ ۱۵)
’’قائم کر نماز سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور پڑھ قرآن فجر میں۔‘‘
وَلَا تَجْھَرْ بِصَلٰوتِکَ وَلَا تُخَافِتْ بِھَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَالِکَ سَبِیْلًا (بنی اسرائیل پ ۱۵)
’’اور نہ بلند کر اپنی نماز میں (تلاوت کی آواز) اور نہ بہت آہستہ کر اسے، اور ڈھونڈ اس کے درمیان کا راستہ۔‘‘
انہی ترغیبات کی وجہ سے اکثر رات کو قرآن مجید کی تلاوت تہجد و نوافل میں کی جاتی ہے۔ خود حضورؐ تلاوت کی کثرت نوافل و تہجد میں فرمایا کرتے تھے۔
اِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ اَنَّکَ تَقُوْمُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَہٗ وَثُلَثَہٗ وَطَائِفَۃُْ مِّنَ الَّذِیْنَ مَعَکَ (المزمل پ ۲۹)
’’بے شک رب تیرا جانتا ہے کہ تو کھڑا ہوتا ہے تقریباً دو تہائی رات اور آدھی اور تہائی تک، اور ایک جماعت ان لوگوں کی جو تیرے ساتھ ہیں۔‘‘
مدارسِ قرآن
قرآن مجید سیکھنے کے لیے مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ خصوصًا مسجد نبویؐ میں اصحابِؓ صُفَّہ، جب کہ مستقل طور پر دینی مدرسہ مخرمہ بن نوفلؓ کے مکان پر دارالقراء کے نام سے مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعتِ عقبہ اولٰی کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیرؓ کو تعلیم قرآن مجید کے لیے بھیجا تھا۔ ایک اور موقع پر ستر قاریوں کو اہل ِ نجد کی تعلیم کے لیے بھیجا جنہیں برمعونہ کے مقام پر شہید کیا گیا۔ یمن کے لشکر کے قاضی کی حیثیت سے حضورؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی تقرری کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے
خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَہٗ۔
’’تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔‘‘
انہی ترغیبات کی وجہ سے حضورؐ کی حیاتِ مبارکہ میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت ہر گھر میں ہوا کرتی تھی۔
وَاذْکُرْنَ مَا یُتْلٰی فِیْ بُیُوْتِکُنَّ مِنْ اٰیٰتِ اللہِ وَالْحِکْمَۃِ (الاحزاب پ ۲۲)
’’اور یاد کیا کرو جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت میں سے۔‘‘
کتابی حفاظت
چونکہ عرب عموماً اَن پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے
ھُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیِّیْنَ رَسُوْلًا مِّنْھُمْ (الجمعہ پ ۲۸)
’’وہ جس نے بھیجا اَن پڑھوں میں رسول انہی میں سے۔‘‘
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُمّی تھے۔
اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ النَّبِیِّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُوْنَہٗ مَکْتُوْبًا عِنْدَھُمْ فِی التَّوْرَاۃِ وَالْاِنْجِیْلِ (اعراف پ ۹)
’’وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اُمّی نبی کی جسے پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات و انجیل میں۔‘‘
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت حالت یہ تھی کہ قریش مکہ میں صرف سترہ کاتبین تھے جو (۱) حضرت عمر بن الخطاب (۲) عثمان بن عفان (۳) علی بن ابی طالب (۴) ابوعبیدہ بن الجراح (۵) طلحہ (۶) ابو سفیان بن حرب بن امیہ (۷) معاویہ بن ابی سفیان (۸) یزید بن ابی سفیان (۹) ابان بن سعید بن العاص بن امیہ (۱۰) خالد بن سعید بن العاص (۱۱) حاطب بن عمرو العامری القریشی (۱۲) ابو سلمہ بن عبد الاسد مخعزومی (۱۳) عبد اللہ بن سعد بن ابی سرم العامری (۱۴) حویطب بن عبد العزٰی عامری (۱۵) جھیم بن ابی الصلت بن مخرقہ بن مطلب بن عبد مناف (۱۶) علاء بن حضرمی (۱۷) اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنھم ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کتابی صورت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:
وَالطُّوْرِ ۔ وَکِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ ۔ فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ (طور پ ۲۷)
’’قسم ہے طور کی۔ اور کتاب کی جو کھلی ہوئی ہے۔ کھلے ہوئے کاغذ پر۔‘‘
ن ۔ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُوْنَ (ن پ ۲۹)
’’قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں۔‘‘
حضرت ابو رافع ؓحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ
حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی الْوَالِدِ اَنْ یَّعْلَمَہُ الْکِتَابَۃَ وَالسَّاحَۃَ وَالرَّمی۔
’’بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ وہ اسے کتابت، تیراکی اور تیر اندازی سکھائے۔‘‘
حضورؐ کو تعلیمِ کتابت کا اتنا اہتمام تھا کہ غزوۂ بدر کے موقع پر غریب کفار کے لیے یہ فدیہ رکھا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ چنانچہ جب ہم کاتبینِ وحی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی تعداد تقریبًا بیالیس نظر آتی ہے جو کہ شانے کی چوڑی ہڈیوں، تختیوں، کھجور کی شاخوں کے ڈنٹھل، سفید پتھر کے ٹکڑوں، رقاع کھال یا باریک جھلی یا کاغذ کے ٹکڑے قطع الادیم، چمڑے کے ٹکڑوں اور اونٹوں کی کاٹھیوں پر لکھا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی باوجودیکہ حضورؐ لکھنا نہیں جانتے تھے۔
وَلَا تَخُطُّہٗ بِیَمِیْنِکَ اِذًالَّاْرتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ (العنکبوت پ ۲۱)
’’اور نہ ہی لکھتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ سے کہ اس وقت البتہ دھوکا کھاتے یہ جھوٹے۔‘‘
لیکن اس کے باوجود مکی دور میں ہی قرآن مجید کی کتابت عام ہو چکی تھی۔
فِیْ صُحُفٍ مُّکَرَّمَۃٍ ۔ مَرْفُوْعَۃٍ مُّطَہَّرَۃٍ ۔ بِاَیْدِیْ سَفَرَۃٍ ۔ کِرَامٍ بَرَرَۃٍ (عبس پ ۳۰)
’’عظمت والے صحیفوں میں ۔ بلند کیے گئے پاک کیے گئے ۔ لکھنے والے ہاتھوں سے ۔ بزرگ نیکو کاروں کے۔‘‘
دوسری جگہ فرمایا:
وَقَالُوْا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَھَا فَھِیَ تُمْلٰی عَلَیْہِ بُکْرَۃً وَّاَصِیْلًا (الفرقان پ ۱۸)
’’اور کہا انہوں نے یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، لکھ لیا ہے ان کو پھر وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح و شام۔‘‘
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام والے واقعہ میں بھی ان کی ہمشیرہ نے ان کو قرآن مجید کے اوراق دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا:
لَسْتَ مِنْ اَھْلِھَا ھٰذَا کِتَابُْ لَّا یَمَسُّہٗ اِلَّا الْمُطَھَّرُوْنَ (بیہقی دلائل النبوۃ)
’’تو اس کا اہل نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے نہیں چھو سکتے سوائے پاکیزہ لوگوں کے۔‘‘
قرآن مجید جب زیر کتابت تھا اس دور میں حضورؐ نے قرآن مجید کے علاوہ دیگر ہر قسم کی تحریرات کی ممانعت کر دی تھی تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ان تفاسیر و حواشی یا احادیث کا اضافہ و اختلاط نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا:
مَنْ کَتَبَ عَنِّیْ غَیْرَ الْقُرْاٰنَ فَلْیُمْحِہٗ۔
’’جس نے مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ لکھا ہو تو اسے مٹا دے۔‘‘
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَکْتُبُ الْاَحَادِیْثَ فَقَالَ مَا ھٰذَا تَکْتُبُوْنَ؟ قُلْنَا اَحَادِیْثَ سَمِعْنَاھَا مِنْکَ قَالَ اَکِتَابًا غَیْرَ اللہِ تُرِیْدُوْنَ؟ مَا اَضَلُّ مِمَّنْ قَبْلِکُمْ اِلَّا مَا اکْتَتَبُوْا مِنَ الْکِتَابِ مَعَ کِتَابَ اللہِ تَعَالیٰ (الحدیث)
’’آئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم احادیث لکھ رہے تھے تو فرمایا تم یہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا احادیث جو ہم نے آپ سے سی ہیں۔ فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب تم چاہتے ہو؟ نہیں گمراہ ہوئے تھے تم سے پہلے مگر لکھتے تھے اور کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ۔‘‘
تدوینِ قرآن
قرآن مجید چونکہ نزولی ترتیب کے مطابق نہیں، اس لیے جب تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا اس وقت تک قرآن مجید کو صحیفہ کی شکل میں اکٹھا کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ بیک وقت مختلف سورتوں کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ حضورؐ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے دورِ خلافت میں مختلف نوشتوں سے ہر سورت کی تمام آیات اکٹھی کی گئیں اور قرآن مجید کو مرتب کیا گیا۔
وَقَدْ کَانَ الْقُرْاٰنَ کُتِبَ کُلُّہٗ فِیْ عَھْدِ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لٰکِنْ غَیْرَ مَجْمُوْعٍ فِیْ وَضْعٍ وَاحِدٍ وَلَا مُرَتّب السُّوَرَ (الاتقان)
’’اور البتہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پورا لکھا جا چکا تھا لیکن یکجا شکل میں نہ تھا اور نہ ہی سورتوں کو مرتب کیا گیا تھا۔‘‘
حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی قیادت میں پچیس مہاجر صحابہؓ اور پچاس انصاری صحابہؓ سے قرآن مجید مرتب کرایا۔ اس کے بعد فتح آرمینیا کے موقع پر حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے مدینہ منورہ واپس پہنچ کر حضرت عثمانؓ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کی قراءتیں ایک قراءت پر مجتمع کی جائے جس پر حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے ذریعے ۲۴ھ آخر یا ۲۵ھ کے اوائل میں قرآن مجید کی کتابت مکمل کروائی اور اس کی سات نقلیں کرا کر کوفہ، شام، بحرین، بصرہ، یمن، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رکھوائیں جن سے نقل شدہ قرآن آج تک دنیا میں صحیح کامل حالت میں موجود ہیں۔
علومِ قرآن
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی علوم کو پانچ شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔
(۱) علم الاحکام
جس میں فرائض و واجبات، حلال و حرام وغیرہ کا بیان ہے۔ اس علم کی تفصیل بیان کرنا فقہاء اور مجتہدین کا کام ہے۔
(۲) علم المناظرہ
اس میں یہود و نصارٰی، مشرکین اور منافقین سے مناظرہ ہے۔ ان پر بحث کرنا متکلمین کا کام ہے۔
(۳) علم تذکیر بآلاء اللہ
اس میں زمین و آسمان، رزق و عزت، انعاماتِ الٰہی و صفات الٰہی کا بیان ہے۔ ان پر بحث کرنا صوفیاء اور مشائخ کا کام ہے۔
(۴) علم تذکیر بایام اللہ
اس میں ان تاریخی واقعات کا ذکر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کو بطور انعام کامیاب فرمایا، یا سرکشوں اور نافرمانوں پر عذاب نازل کر کے انہیں عبرت کا سامان بنایا۔
(۵) علم تذکیر بما بعد الموت
اس میں موت اور موت کے بعد آنے والے واقعات، مسئلہ حشر نشر، حساب کتاب، میزان اور جنت و دوزخ کا بیان ہے۔ ان آخری دو علوم پر بحث کرنا واعظین کا طریقہ ہے۔
علومِ تفسیر قرآن
تفسیر لغوی طور پر فَسَّرَ بمعنی کشف سے ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ان ہی معانی میں ذکر کیا گیا ہے:
وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ (المدثر پ ۲۹)
’’اور صبح کی جب روشن ہو۔‘‘
وَلَا یَاْتُوْنَکَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰکَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِیْرًا۔ (الفرقان پ ۱۹)
’’اور وہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال مگر ہم پہنچا دیتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر۔‘‘
جبکہ اصطلاح میں تفسیر سے مراد:
عِلْمُْ یُبْحَثُ فِیْہِ عَنْ مَعْنی نَظَمِ الْقُرْاٰن بِحَسْبِ الْقَوَانِیْنِ الْعَرَبِیَّۃِ وَالْقَوَاعِدِ الشَّرْعِیَّۃِ بِقَدَرِ طَاقَۃِ الْبَشَرِیَّۃِ۔
’’ایسا علم جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے معنی پر عربی زبان کے قوانین اور شریعت کے قاعدوں کو پیش نظر رکھ کر انسانی طاقت کے مطابق بحث کی جاتی ہے۔‘‘
تاہم اپنی رائے اور سوچ سے تفسیر کرنے کی ممانعت ہے۔ کتاب اللہ کا جو مفہوم کتاب و سنت سے ثابت ہو گا اسے تفسیر کہیں گے اور اسی مفہوم کے موافق مسائل و معارف کے استنباط کو تاویل کہیں گے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ تفسیر میں تین چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔
(۱) ہر کلمہ کو معنی حقیقی یا مجاز معروف پر محمول کرنا۔
(۲) سیاق و سباق کو ملحوظ رکھنا تاکہ کلام بے ربط نہ ہو۔
(۳) حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کی تفسیر کے خلاف نہ ہو۔
اگر پہلی شرط فوت ہو گئی تو تاویل قریب ہے۔ اگر دوسری شرط فوت ہو گئی تو تاویل بعید ہے۔ لیکن اگر تیسری شرط فوت ہو گئی تو تحریف ہے اور کفر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مَنْ فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِرَایِہٖ فَقَدْ کَفَرَ۔
’’جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی تو تحقیق کافر ہو گیا۔‘‘
تفسیر کی ضرورت
اَفَلَا یَتَدَبّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُھَا (محمد پ ۲۶)
قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے تفسیر کی ضرورت یوں بیان فرمائی:
وَاَنْزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْھِمْ (النحل پ ۱۴)
’’اور اتارا ہم نے آپ کی طرف ذکر تاکہ سمجھائیں آپؐ لوگوں کو وہ جو اتاری گئی ہے ان کے لیے۔‘‘
اسی طرح حضورؐ کی بعثت کا مقصد بھی تعلیم کتاب اور حکمت و تفسیر ہی تھا۔
کَمَا اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا مِّنْکُمْ یَتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَیُزَکِّیْکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکَمَۃَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَّا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (بقرہ پ ۲)
’’جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، پڑھتا ہے تم پر آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے۔‘‘
حضورؐ نے جو بھی تفسیر بیان فرمائی وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی تھی۔
وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوٰی۔ اِنْ ھُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی۔ (النجم ۲۷)
تفسیر کے لیے ضروری علوم
امام سیوطیؒ کے مطابق یہ پندرہ علوم مفسر کے لیے ضروری ہیں۔ (۱) لغت عربیہ (۲) علم نحو (۳) علم صرف (۴) علم اشتقاق (۵) علم معانی (۶) علم بیان (۷) علم بدیع (۸) علم قراءت (۹) علم اصول الدین (۱۰) علم اصول فقہ (۱۱) علم اسباب النزول والقصص (۱۲) علم ناسخ و منسوخ (۱۳) علم فقہ (۱۴) علم حدیث مع علم اسماء الرجال والاسناد (۱۵) اور علم الوھبی۔ جبکہ دیگر علماء کے نزدیک یہ علوم بھی ضروری ہیں (۱۶) علم کلام (۱۷) علم تاریخ (۱۸) علم جغرافیہ (۱۹) علم الزہد والرقاق (۲۰) علم الاسرار (۲۱) علم الجدل والخلاف (۲۲) علم السیرۃ (۲۳) علم الحقائق (۲۴) علم الحساب (۲۵) اور علم المنطق۔
تفسیری ادوار
- صحابہ کرامؓ کے دور میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر پوچھی جاتی تھی۔ یہ پہلا دور کہلایا۔
- حضورؐ کی رحلت کے بعد حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ سے تفسیر پوچھی جاتی تھی۔ یہ دوسرا دور کہلایا۔
- تیسرے دورِ تابعین میں حضرت سعید بن جبیرؓ نے باقاعدہ کتابی شکل میں تفسیر لکھ کر عبد الملک بن مروان کے دربارِ خلافت میں بھیجی جو کہ آج تفسیر عطاء بن دینار کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے علاوہ اس دور میں مجاہدؒ، عکرمہؒ، حسن بصریؒ، ضحاکؒ، اور قتادہؒ وغیرہ مشہور ہیں۔
- چوتھے دور میں کتب کی تدوین کے وقت پہلے سے رائج طریقے سے ہٹ کر تفسیری کتابوں کو علیحدہ تحریر کیا جانے لگا اور تفسیری اقوال کے لیے اسناد کی شرط ختم کر دی۔
- پانچویں دور میں جو عباسی خلافت سے شروع ہو کر آج تک چلا آ رہا ہے اس دور میں ہر ماہر فن نے اپنے فن کے انداز میں تفسیر لکھی۔ چنانچہ زجاجؒ نے اپنی تفسیر میں، واحدی نے البسیط میں، اور ابوحیان نے البحر المحیط میں نحوی مہارت کا ثبوت دیا۔ جبکہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں علوم عقلیہ اور حکماء و فلاسفہ کے اقوال پیش کیے۔
مختصرًا یہ کہ تفاسیر قرآن بنیادی طور پر چھ اقسام میں منحصر ہو گئیں۔
- فقہی تفاسیر: جن میں صرف ان آیات کی تفسیر کی گئی ہے جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جیسے احکام القرآن۔
- ادبی تفاسیر: ان میں فصاحت و بلاغت کو پیشِ نظر رکھا گیا۔
- تاریخی تفاسیر: ان میں تاریخی واقعات کو پیشِ نظر رکھا گیا جیسے ابن عربیؒ اور ابو عبد الرحمٰن السلمیؒ کی تفاسیر۔
- نحوی تفاسیر: ان میں نحوی مباحث پیشِ نظر رکھے گئے جیسے اعراب القرآن للرازیؒ۔
- لغوی تفاسیر: جیسے مفردات القرآن للامام راغب الاصفہانیؒ۔
- کلامی تفاسیر: جن میں عقائد پر بحث کی گئی ہو جیسے امام رازیؒ کی تفسیر کبیر اور زمحشریؒ کی کشاف وغیرہ شامل ہیں۔
سخت سزائیں اور کتب و اُمم سابقہ
محمد اسلم رانا
مغرب زدہ افراد کا ایک طبقہ ہے جو اسلامی حدود کے نفاذ کا خواہاں نہیں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ اسلامی سزائیں سخت ہیں، غیر انسانی ہیں اور وحشیانہ ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ خیال و تاثر محض مغرب سے مرعوبیت اور مسحوریت کا نتیجہ ہے ورنہ اسلامی سزائیں جہاں نافذ ہوتی ہیں وہ معاشرہ جرم و گناہ سے تقریباً پاک ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں سخت سزائیں اسلام ہی نے مقرر نہیں کی ہیں بلکہ اسلام سے قبل آسمانی مذاہب میں بھی اسی نوعیت کی سزائیں تھیں اور یہ سزائیں آج تک ان کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں جنہیں اہل مغرب (عیسائی اور یہودی) بھی مذہبی اور مقدس مانتے ہیں۔ اس ضمن میں کتبِ سابقہ کا ایک مختصر سا مطالعہ حسب ذیل ہے۔
کتب سابقہ کے ایک مروّجہ مجموعہ بائبل کی پہلی پانچ کتابیں تورات کہلاتی ہیں۔ یہودی ان کی بہت تعظیم کرتے اور قابلِ عمل سمجھتے ہیں۔ عیسائی بھی ان کی عظمت و تقدس کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے۔ یہودی یا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ ان کی مقدس کتابوں کی رو سے قومِ یہود خدا تعالیٰ کی برگزیدہ، چنیدہ، اپنی اور مقدس قوم ہے۔ یہ لوگ خدا کے فرزند ہیں، نبوت اور رسالت صرف اسی قوم کے لیے مخصوص ہے، غیر یہودی کتوں کی مثل ہیں، نجات کی بلاہٹ محض یہودیوں کے لیے ہے غیر اقوام کے لیے نہیں (پادری ڈملو کی تفسیر بائبل صفحہ ۸۵)۔
اس عظمت و بزرگی کے ساتھ ساتھ کتب مقدسہ سے یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ یہودی ایک بڑی سرکش اور نافرمان قوم ہیں۔ ان کی سرکشی اور باغیانہ خصلتوں کے پیشِ نظر ان کی شریعت بھی بڑی سخت مقرر کی گئی تھی۔ مثلاً ان کے ہاں ذبیحہ کا گوشت پہلے اور دوسرے دن تو کھایا جا سکتا تھا لیکن تیسرے دن کھانے کی ممانعت تھی۔ خلاف ورزی کی سزا جماعت سے کاٹا جانا تھی (کتاب احبار باب ۱۹ آیت ۸)۔ آتشیں قربانی کا گوشت یا اپنی سکونت گاہ میں پرند یا چرند کا خون کھانے (احبار باب ۷ آیت ۲۵) حائضہ کے ساتھ صحبت (احبار باب ۲۰ آیت ۱۸) اور کفارہ کے دن اپنی جان کو دکھ نہ دینے کی سزا بھی جماعت سے کاٹا جانا تھی (احبار باب ۲۳ آیت ۲)۔ جماعت سے کاٹے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص بنی اسرائیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وعدوں اور موعودہ برکتوں میں شامل نہیں رہتا، نامختون اور غیر قوم کا فرد شمار کیا جاتا ہے (پادری ڈملو کی تفسیر ص ۵۹)
سزائے موت
قاتل کا مارا جانا تو بآسانی سمجھ میں آتا ہے (احبار باب ۲۴ آیت ۱۸) لیکن زنا اور لواطت کی سزا بھی موت ہی ہے (احبار باب ۲۰) جانور سے جماع کرنے والا بھی جان سے مارا جائے (احبار باب ۲۰ آیت ۴۵) اگر کسی شخص کا بیل ماروکھنڈا ہو اور مالک اسے باندھ کر نہ رکھے اور وہ بیل کسی مرد یا عورت کو ٹکر مار کر اس کی جان لے لے تو بیل کو سنگسار کیا جائے، مالک کی سزا بھی موت ہے۔ جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے وہ قطعی مارا جائے (خروج باب ۲۱ آیت ۱۶) نقب زنی کرتے ہوئے چور کو اگر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں (خروج باب ۲۲ آیت ۲) توبہ توبہ وہ کتنی سخت شریعت تھی جس کے مطابق اگر کوئی شخص کاہن (یہودی مولوی) سے گستاخی سے پیش آئے یا قاضی کا کہا نہ مانے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے (استثنا باب ۷ آیت ۱۲)
کوڑے
اگر لوگوں میں کسی قسم کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان سے انصاف کریں، تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر کے خلاف فتوٰی دیں۔ اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے اور اسے چالیس کوڑے لگیں زیادہ نہیں (استثنا باب ۲۵ آیت ۱ تا ۳)
سنگساری
تورات میں کئی جرموں کی سزا سنگساری ہے۔ لکھا ہے جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے (احبار باب ۲۴ آیت ۱۶) اسی طرح جو شخص اور معبودوں سورج، چاند یا اجرام فلکی کی پوجا کرے اس کی سزا شہر کے پھاٹکوں سے باہر لے جا کر سنگسار کرنا ہے کہ وہ مر جائے (استثنا باب ۱۷ آیت ۶) ترغیبِ شرک کی سزا قتل ہے (استثنا باب ۱۲) تورات پڑھتے وقت قاری کے ذہن پر اس کے شرعی احکام کی سختی کا گہرا تاثر قائم ہوتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنگسار کریں (احبار باب ۲۰ آیت ۲۷) ماں باپ کے نافرمان بیٹے کو شہر کے سب لوگ سنگسار کریں کہ وہ مر جائیں (استثنا باب ۲۱ آیت ۲۱) یہودی سبت کو مانتے ہیں یعنی ہفتہ کے روز کچھ کام نہیں کرتے۔ حرمتِ سبت کا حکم نیا نیا تھا، لوگ اس کی عظمت و اہمیت ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے تھے۔ صحرا نوروی کے دنوں ایک یہودی سبت کے دن لکڑیاں اکٹھی کرتے پکڑا گیا، جماعت نے اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا اور حضرت موسٰی علیہ السلام نے بحکم الٰہی اسے لشکرگاہ سے باہر لے جا کر خود سنگسار کرایا اور وہ مر گیا (گنتی باب ۱۵ آیت ۳۶)
آگ میں جلانا
ہمارے بہت سارے معزز قارئین کے لیے یہ امر انتہائی عجیب اور اچنبھا معلوم ہو گا کہ تورات میں بعض جرائم کی سزا آگ میں جلانا بھی مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص بیوی اور ساس دونوں کو رکھے تو تینوں جلا ڈالے جائیں۔ (احبار باب ۲۰ آیت ۱۴) کپڑا جتنا سفید ہو گا اس پر داغ اتنا ہی برا لگے گا۔ چنانچہ اگر کاہن کی بیٹی فاحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ عورت آگ میں جلائی جائے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے (احبار باب ۲۱ آیت ۹)
تورات کے مذکورہ احکام پر باقاعدہ عمل کیا جاتا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی زنا کی سزا سنگساری تھی (انجیل یوحنا باب ۸) ؟؟ کو شریعت کی مخالفت اور موسٰیؑ کی رسموں کو بدلنے کے الزام میں سنگسار کیا گیا تھا (کتاب اعمال باب ۶) صدیوں بعد فرانس میں جون آف آرک نامی نوجوان خاتون کو جادوگری کے الزام میں جلا دیا گیا تھا۔ تورات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جرائم کی سرکردگی پر سزا کا مطلب برائیوں سے پاک معاشرہ کا قیام تھا۔ جب لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں جرم کرنے پر اتنی سخت سزا ضرور ملے گی تو وہ قانون شکنی سے باز رہیں گے اور سزا کے اجراء سے عبرت پکڑیں گے۔ نافرمان بیٹے کو سنگساری کے حکم کے بعد لکھا ہے کہ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا تب سب اسرائیلی ڈر جائیں گے۔ کچھ اسی طرح کے الفاظ کاہن کی شان میں گستاخی پر سزا دینے کے ضمن میں بھی وارد ہیں کہ سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی نہیں کریں گے (استثنا باب ۱۷ آیت ۱۳)
ہندومت
مشہور ہندو قانون دان منّو کے دھرم شاستر میں ہندوؤں کی چاروں ذاتوں (برہمن، کشتری، ویش، شودر) کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اعلٰی ذات برہمنوں کو معمولی سزاؤں پر اکتفا کیا جاتا ہے، تاہم سخت سزاؤں کا تصور اپنی جگہ قائم ہے مثلاً برہمن، کشتری، ویش کی عورت شوہر وغیرہ سے محفوظ ہو یا نہ اس سے زنا کرنے والے شودر کا عضو تناسل قطع کرنا، تمام دولت کو چھین لینا اور قتل کی سزا دینی چاہیئے۔ اگر وہ غیر محفوظ عورت سے جماع کرے تو اسے دونوں متذکرہ صدر سزائیں اور قتل کی سزا دینی چاہیئے (منو کا دھرم شاستر ادھیائے ۸ اشلوک ۳۷۴) جس عضو سے دوسرے کی چیز چرائے اسی عضو کو قطع کرنا چاہیے تاکہ پھر ایسا کام نہ کرے (۸ : ۳۳۴)
چند برس پیشتر بھارت کی ایک اعلیٰ عدالت نے نسوانی مقدمات کے سلسلہ میں کوڑوں کی اسلامی سزا کی حمایت کی تھی۔ اگر جرم کو روکنا مقصود ہے تو پھر مجرم کے ساتھ چہلیں نہیں کی جانی چاہئیں۔ القصہ ہمیں اسلامی شریعت کو ببانگ دہل اپنانا چاہیئے اور ہرگز پرواہ نہیں کرنی چاہیئے کہ اس پر دنیا کیا کہے گی۔ بفضلہٖ تعالیٰ ہم حق پر ہیں (قرآن مجید سورہ یس آیت ۱۴) چنانچہ ہمیں حق پر ڈٹ کر دنیا والوں کی اٹکلوں کی طرف مطلق توجہ نہیں دینی چاہیئے۔ جن قوانین، اقدار اور امور و احکام نے ڈیڑھ ہزار برس پیشتر عالمِ انسانیت سے اپنی صداقت کی مہر لگوائی تھی اگر انہیں خلوصِ نیت سے آج بھی اپنایا جائے تو
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ۔ نفاذ اسلام کی جدوجہد میں معاون یا رکاوٹ؟
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
ہفت روزہ زندگی کے ایک گزشتہ شمارہ (۱۵ تا ۲۱ دسمبر ۱۹۸۹ء) میں ’’ایران اور انقلاب ایران‘‘ پر بحث و تمحیص کے حوالہ سے کالاگوجراں سے جناب جعفر علی میر کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے انقلاب ایران اور اس کے اثرات کے بارے میں اپنے تاثرات قلمبند کیے ہیں۔ راقم الحروف کو ۱۹۸۷ء میں پاکستانی علماء کرام، وکلاء، دانشوروں کے ایک وفد کے ساتھ ایران جانے اور وہاں گیارہ روزہ قیام کے دوران انقلابی راہنماؤں سے ملنے اور انقلاب کے اثرات و نتائج کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل چکا ہے اور اس مشاہدے کے بارے میں میرے تاثرات قومی پریس کے ذریعے منظر عام پر آچکے ہیں۔ اسی لیے جناب جعفر علی میر کے مضمون کے اس عنوان نے مجھے چونکا دیا کہ ’’ایران کے سنیوں پر شیعہ قوانین نافذ نہیں ہے‘‘۔ کیونکہ یہ بات واقعات سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتی۔ پھر مضمون کے اس حصے نے حیرت و استعجاب کو دوچند کر دیا کہ
’’نفاذ فقہ جعفریہ کا مطالبہ فقط اہل تشیع کے لیے کیا جاتا ہے اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا موقف یہ ہے کہ ہر مسلک کے پیروکاروں کو ان کی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہو جیسا کہ ایران میں ہے۔ وہاں اہل سنت کو مکمل آزادی ہے، ان کے مدارس دینیہ و مساجد موجود ہیں، پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے کسی قانون کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔‘‘
یوں محسوس ہوتا ہے کہ جناب جعفر علی میر صاحب ابھی تک خود ایران نہیں گئے ہیں اور اگر انہیں وہاں جانے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھنے پر اکتفاء کیا ہے اور دوسرے رخ پر نظر ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی، ورنہ ان کے تاثرات اس درجہ خلاف واقعہ اور یک طرفہ نہ ہوتے۔
جہاں تک انقلاب ایران کے سماجی و سیاسی اثرات اور علاقائی و عالمی سیاست میں انقلابی حکومت کے رول کا تعلق ہے اس پر زیر نظر مضمون میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی عالم اسلام کے ساتھ ایران کی انقلابی حکومت کے تعلقات اور رویے کو زیر بحث لانا مقصود ہے۔ مگر جعفر میر صاحب کے مضمون کے عنوان اور مندرجہ بالا اقتباس کے حوالہ سے اور ایران میں اپنے گیارہ روزہ قیام کے مشاہدات کی روشنی میں مندرجہ ذیل دو پہلوؤں پر چند ضروری گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصل صورت حال قارئین کے سامنے آسکے۔
- ایران میں مقیم اہل سنت کے ساتھ انقلابی حکومت کا رویہ کیا ہے؟
- اور پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات کے پس منظر میں شیعہ تحریکات کے سرپرست کی حیثیت سے ایران کی انقلابی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے؟
جہاں تک ایران میں مقیم اہل سنت کا تعلق ہے، اس بارے میں سب سے پہلے ان حقائق کا ادراک ضروری ہے کہ ایران کی مجموعی آبادی میں اہل سنت کا تناسب پچیس فیصد سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ دو صوبوں بلوچستان اور کردستان بلکہ ایرانی ترکمانستان میں بھی اہل سنت کی واضح اکثریت ہے اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایران کے چاروں طرف سرحدی علاقوں میں اہل سنت اکثریت میں ہیں جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ صفیوں کے اقتدار سے قبل پورا ایران سنی اکثریت کا ملک تھا لیکن صفیوں نے طاقت کے زور سے لوگوں کو زبردستی شیعہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا اور راسخ العقیدہ سنی مسلمان ان کے ظلم و جبر کی تاب نہ لاتے ہوئے وسطی ایران سے سرحدی علاقوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور اس طرح ایران کو بالجبر شیعہ ریاست بنا دیا گیا۔
مزید تفصیلات میں جائے بغیر میں ان مسائل کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کا اس وقت ایرانی اہل سنت کو سامنا ہے اور جن مسائل کے حل کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کسی تحریک اور منظم حمایت کا وجود نہیں ہے جس سے اس طبقہ کی مظلومیت دوچند ہو جاتی ہے۔
- تین صوبوں میں اہل سنت کی واضح اکثریت ہونے کے باوجود صوبائی حکومتوں کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے اقتدار میں ان کی کسی درجہ میں بھی شرکت نہیں، بلکہ ملازمتوں میں بھی ان کا تناسب بہت کم ہے۔ گورنر اور اعلیٰ افسران مرکز کی طرف سے آتے ہیں جو غیر سنی ہونے کے علاوہ غیر مقامی بھی ہوتے ہیں اور عام ملازمتوں کے دروازے بھی مقامی سنی آبادی پر بند ہیں جس سے غیریت اور محرومیت کا احساس دن بدن بڑھ رہا ہے۔
- ملکی آبادی میں کم از کم پچیس فیصد ہونے کے باوجود قومی اسمبلی میں اہل سنت کی نمائندگی کا تناسب یہ ہے کہ ۱۹۸۷ء میں جب ہم ایران گئے، دو سو ستر کے ایوان میں سنی ارکان کی تعداد صرف چودہ تھی۔
- تہران میں لاکھوں کی تعداد میں سنی آباد ہیں لیکن انہیں اپنے لیے الگ مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور شیعہ سنی اتحاد کا جو پراپیگنڈا زور و شور سے کیا جاتا ہے اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سنی آبادی اپنا الگ تشخص قائم کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے میزبانوں سے بات کی تو معلوم ہوا کہ تہران میں ایک پلاٹ اہل سنت کی مسجد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا لیکن جس سنی راہنما کو یہ پلاٹ دیا گیا تھا اسے اس جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا کہ اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے سعودی حکومت سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ہمارے شدید اصرار اور کوشش کے باوجود ہمارے میزبان وہ پلاٹ ہمیں دکھانے پر تیار نہ ہوئے جو خود ان کے بقول اہل سنت کی مسجد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اور ابھی تک وہاں مسجد کی تعمیر کے کوئی امکانات واضح نہیں ہوئے تھے۔
- ایرانی دستور میں ہر طبقہ کو اپنے حقوق و مسائل کے لیے تنظیم سازی کا حق دیا گیا ہے لیکن یہ حق عملاً اہل سنت کو حاصل نہیں ہے۔ کردستان کے ایک عالم احمد مفتی زادہ صرف اس جرم میں گرفتار ہوئے کہ انہوں نے اہل سنت کے حقوق کے لیے ایک تنظیم قائم کرنے کی جسارت کرلی تھی جو انقلابی حکومت کے ہاں ناقابل معافی قرار پائی۔ ان کے علاوہ سراوان کے صوفی دوست محمد، سرخس کے مولانا محی الدین، اور ایران شہر سے قومی اسمبلی کے سابق رکن مولانا نظر محمد بھی اہل سنت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔
- ایران کے صرف قم شہر کے مدارس میں پاکستان کے ایک ہزار سے زائد شیعہ طلبہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ایران کے سنی طلبہ کو پاکستان کے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ طلبہ کو پاسپورٹ نہیں دیا جاتا، درخواست دینے والے طلبہ سی آئی ڈی کی مستقل نگرانی کی زد میں آجاتے ہیں اور جو نوجوان کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں واپسی پر جیل کی سلاخیں ان کی منتظر ہوتی ہیں۔
- ایران کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے سلسلہ میں سنی طلبہ سے ترجیحی سلوک روا رکھا جاتا ہے، مذہبی رجحانات کے حامل طلبہ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، صرف ان طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے جو مذہبی لحاظ سے قدرے آزاد ہوں اور ان کی برین واشنگ آسانی سے کی جا سکے۔
- ایران کا سرکاری مذہب اثنا عشری ہے۔ ملک کا پبلک لاء اسی فقہ کے مطابق ہے اور اس کا اطلاق سنیوں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح باقی آبادی پر ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں
- ایرانی دستور کے ’’اصول کلی‘‘ میں اصل دوازدہم (بارہواں اصول) یوں درج ہے:
’’دین رسمی ایران، اسلام و مذہب، جعفری اثنا عشری است و ایں اصل الی الابد غیر قابل تغیر است و مذاہب دیگر اسلامی اہم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبل و زیدی دار ای احترام کامل میباشند و پیر وان ایں مذاہب درانجام مراسم مذہبی طبق فقہ خود شاں آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیہ (ازدواج، طلاق، ارث، و وصیت) و دعاوی مربوط بہ آن در داد گاہ ہا رسمیت دارند و در ہر منطقہ کہ پیروان ہر یک ازیں مذاہب اکثریت داشتہ باشند مقدرات محلی در حدود و اختیارات شوراہا برطبق آں مذہب خواہد بود باحفظ حقوق پیرواں سایر مذاہب۔‘‘
ترجمہ: ’’ایران کا سرکاری دین اسلام اور سرکاری مذہب جعفری اثنا عشری ہے اور یہ اصل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل تبدیل ہے۔ دیگر اسلامی مذاہب مثلاً حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور زیدی پوری طرح قابل احترام ہوں گے اور ان مذاہب کے پیروکار اپنی مذہبی رسوم کو اپنی فقہ کے مطابق بجا لانے میں آزاد ہوں گے اور دینی تعلیم و تربیت اور شخصی قوانین (نکاح، طلاق، وراثت اور وصیت یعنی پرسنل لاء) اور ان سے متعلقہ دعاوٰی کی سماعت کا عدالتوں میں قانونی حق رکھیں گے اور جن علاقوں میں ان میں سے کسی ایک مذہب کے پیروکاروں کی اکثریت ہوگی وہاں لوکل قوانین مجالس مشاورت کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کے موافق بنا سکیں گے بشرطیکہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے حقوق محفوظ ہوں۔‘‘
- ایرانی دستور کی اصل یک صد و پانزدہم (دفعہ ۱۱۵) میں صدر مملکت کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایرانی النسل اور دیگر شرائط کا حامل ہونے کے ساتھ ایران کے سرکاری مذہب (جعفری اثنا عشری) کا پیروکار ہو۔ اور اصل یک صد و بیست و یکم (دفعہ ۱۲۱) میں صدر ایران کے حلف نامہ میں اسے اس حلف کا پابند کیا گیا ہے کہ
’’پاسدار مذہب رسمی و نظام جمہوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم۔‘‘
ترجمہ: ’’میں ریاست کے سرکاری مذہب (جعفری اثنا عشری) جمہوری اسلامی نظام اور دستور کی پاسداری کروں گا۔‘‘
- دستور کی دفعہ ۷۲ میں مجلس شوریٰ ملی (قومی اسمبلی) کو پابند کیا گیا ہے کہ
’’مجلس شوریٰ ملی نمی تواند قوانینی وضع کند کہ بااصول و احکام مذہب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشتہ باشد۔
ترجمہ: ’’قومی اسمبلی ملک کے دستور اور سرکاری مذہب (جعفری اثنا عشری) کے منافی کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔‘‘
ان واضح دستوری دفعات کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہے۔ صدر ایران شیعہ مذہب کی پاسداری کا پابند ہے۔ قومی اسمبلی شیعہ مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ اور ملک کا عمومی قانون (پبلک لاء) جعفری اثنا عشری مذہب کے مطابق ہے جس کا اطلاق شیعہ سنی سب پر ہوتا ہے۔ اس لیے جناب جعفر علی میر کے اس ارشاد کو مبنی بر حقیقت کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایران میں سنیوں پر شیعہ قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔
جناب جعفر علی میر کے مضمون کے جواب میں دوسری گزارش یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات کے تسلسل نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایرانی انقلاب کے اثرات پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان میں نفاذ اسلام کی تحریکات کے حق میں مثبت نہیں رہے اور ایرانی انقلاب سے پڑوسی ممالک کی نفاذ اسلام کی تحریکات کو وقتی طور پر جو توقعات وابستہ ہوگئی تھیں، نتائج ان کے برعکس سامنے آئے ہیں۔ راقم الحروف خود ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ایران کی انقلابی قیادت سے واضح مذہبی اختلاف کے باوجود انقلاب ایران کا خیرمقدم کیا تھا اور اس کے حق میں خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کیا تھا، صرف اس خیال اور جذبہ سے کہ عقائد کے اختلاف کے باوجود بہرحال ایران کا انقلاب ایک کامیاب مذہبی انقلاب ہے جو آج کے دور میں کمیونسٹ، سیکولر، اور مغربی جمہوریت کے پرستار سیاسی حلقوں پر ایک ضرب کاری ہے اور مذہبی اختلاف کے باوجود نفاذ اسلام کی جدوجہد میں ایران کی انقلابی قیادت کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ توقع تھی کہ انقلاب ایران کے بعد پاکستان کے شیعہ حلقے پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ نفاذ شریعت اسلامیہ کی جدوجہد میں ہمارے معاون ہوں گے اور ان کا مذہبی جوش و خروش ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو ااور انقلاب ایران کے حوالے سے پاکستان میں جو نئی شیعہ تحریکات ابھریں انہوں نے اہل تشیع کے لیے الگ اور متوازی پبلک لاء کا مطالبہ کر کے نفاذ اسلام کی جدوجہد کو نظریاتی محاذ پر سبوتاژ کر کے رکھ دیا۔
انقلاب ایران سے قبل پاکستان کے شیعہ حلقے نفاذ اسلام کی جدوجہد میں کسی اصولی اختلاف کے بغیر ہمارے ساتھ تھے اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ملک کا پبلک لاء ایک ہو۔ چنانچہ ۳۱ علماء کرام کے ۲۲ دستوری نکات میں مندرجہ ذیل اصول (نکتہ ۹) پر مولانا مفتی جعفر حسین اور مولانا مفتی کفایت حسین کے دستخط موجود ہیں کہ
’’مسلمہ اسلامی فرقوں کو حدود قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیرؤوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے۔ ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذاہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا کرنا مناسب ہوگا کہ ان کے قاضی یہ فیصلہ کریں۔‘‘
اس طرح سنی اور شیعہ دونوں حلقے اس امر پر متفق تھے کہ پبلک لاء ایک ہوگا اور شخصی قوانین (پرسنل لاء) میں مسلمہ اسلامی فرقوں کو اپنے اپنے مذہبی قوانین پر عمل کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن ایرانی انقلاب کے بعد ’’تحریک نفاذ فقہ جعفریہ‘‘ کی بنیاد رکھ دی گئی اور مطالبہ یہ ہوا کہ پرسنل لاء میں نہیں بلکہ پورے قانونی نظام میں فقہ جعفریہ کو متوازی قانون کے طور پر نافذ کیا جائے۔ اس مطالبہ کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے دو گروپ کام کر رہے ہیں اور دونوں خود کو انقلاب ایران کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ دونوں گروپوں نے اس بنیاد پر سینٹ میں زیر بحث ’’شریعت بل‘‘ کی مخالفت کی۔ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے میدان عمل میں آنے کا منطقی اور نظریاتی نتیجہ یہ سامنے آیا کہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی اور نفاذ کا مطالبہ فرقہ وارانہ مطالبہ قرار دے دیا گیا۔
انقلاب ایران کے بعد اس حوالہ سے پاکستان میں ابھرنے والی شیعہ جدوجہد کا یہ کردار تاریخ میں اپنے منفی نتائج کے لحاظ سے ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا کہ سیکولر حلقوں کو نفاذ اسلام کی جدوجہد کے خلاف ایسا ہتھیار دے دیا گیا ہے جسے استعمال کرنے میں لادین عناصر اس سے قبل کبھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے لیکن اب وہ اسے پوری مہارت اور کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ کی مخالفت میں سیکولر اور مفاد پرست عناصر پہلے بھی فقہی اختلافات اور فرقہ وارانہ کشمکش کا حوالہ دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کس فرقے کا اسلام نافذ کیا جائے؟ لیکن علماء کے ۲۲ دستوری نکات ان کے اس پروپیگنڈے کا مسکت جواب تھے اور دستوری مسائل پر تمام مکاتب فکر کے متفقہ موقف کے سامنے سیکولر حلقوں کی یہ منطق بے اثر ثابت ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ جب ملک میں شریعت اسلامیہ کی بالادستی اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے ساتھ ہی فقہ جعفریہ کے متوازی نظام کا مطالبہ کھڑا ہو جاتا ہے تو سیکولر عناصر کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار آجاتا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے اور اس سے مذہبی مناقشت بڑھے گی اس لیے نفاذ اسلام کی طرف عملی قدم بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
یہ مسئلہ راقم الحروف نے ۱۹۸۷ء میں اپنے دورۂ ایران کے موقع پر معروف انقلابی راہنما جناب آیت اللہ جنتی کے سامنے پاکستانی وفد کی موجودگی میں پیش کیا تھا اور انہیں اس مشکل سے آگاہ کیا تھا کہ فقہ جعفریہ کے پبلک لاء کے طور پر متوازی نفاذ کے مطالبہ نے سیکولر حلقوں کے مقابلہ میں نظریاتی محاذ پر ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ وفد کے ارکان گواہ ہیں کہ جناب آیت اللہ جنتی نے ہمارے موقف کو درست قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پبلک لاء ایک ہی ہو سکتا ہے جو اکثریتی آبادی کی فقہ کے مطابق ہونا چاہیے، البتہ پرسنل لاء میں آپ اہل تشیع کو آزادی دیں۔ ہم نے عرض کیا کہ پرسنل لاء میں اہل تشیع کے جداگانہ حق سے ہم نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی انکار نہیں کیا۔
آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم پرسنل لاء میں اہل تشیع کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے لیکن پبلک لاء ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا بھر کا مسلمہ اصول ہے اور خود ایرانی دستور میں بھی اس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے اہل تشیع کو اپنی اس جدوجہد اور موقف پر بہرحال نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ ملک کی لادین اور سیکولر قوتوں کے سوا کسی کو نہیں ہے۔
آخر میں جناب جعفر علی میر اور ان کے رفقاء سے عرض کروں گا کہ اہل سنت کے موقف میں کوئی ابہام، تضاد، یا نا انصافی نہیں ہے، وہ اپنے لیے وہی حقوق مانگتے ہیں جو ایران میں شیعہ اکثریت کو دستوری طور پر حاصل ہیں اور ان کا یہ مطالبہ بالکل حقیقت پسندانہ اور مبنی بر انصاف ہے کہ
- پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے۔
- صدر اور وزیراعظم کے لیے سنی ہونا شرط قرار دیا جائے۔
- ملک کا پبلک لاء اکثریتی فقہ کے مطابق ہو اور شیعہ سمیت تمام اقلیتی آبادیوں کو پرسنل لاء میں اپنے مذہب پر عمل کا حق دیا جائے۔
- قومی اسمبلی کو پابند کیا جائے کہ وہ اہل سنت کے مذہب کے منافی قانون سازی نہ کر سکے۔
امید ہے کہ تمام سنجیدہ شیعہ حلقے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان مطالبات کا جائزہ لیں گے اور سیکولر حلقوں کی تقویت کا باعث بننے کی بجائے اپنے ملک کی اکثریتی آبادی کا ساتھ دیں گے۔
نصابِ تعلیم کی تشکیلِ جدید ۔ کیوں اور کیسے؟
مولانا سعید احمد پالنپوری
(یہ مضمون ’’نصابِ تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت‘‘ کے موضوع پر منعقد ہونے والے ایک علمی اجتماع میں پڑھا گیا اور دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ’’ماہنامہ دارالعلوم‘‘ میں شائع ہوا۔ ’’دارالعلوم‘‘ کے شکریہ کے ساتھ اسے قارئین ’’الشریعہ‘‘ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارہ)
نصابِ تعلیم کی تشکیلِ جدید کا مسئلہ بار بار اٹھتا رہتا ہے۔ اخبارات و مجلّات کی سطح سے لے کر عام محفلوں تک اس کا چرچا ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ رائج الوقت نصابِ تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ مگر ضرورت کیوں ہے؟ یہ بات ابھی تک منقح نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس نقطہ پر گفتگو کر لی جائے۔ یہ بات سب ہی حضرات جانتے ہیں کہ دینی تعلیم کے تین مرحلے ہیں اور دینی تعلیم دینے والے اداروں کے مقاصد مختلف ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تعلیم کے مراحل اور اداروں کے مقاصد سے بحث کر لی جائے، اس کے بعد ہی کوئی لائحہ عمل تجویز کیا جا سکتا ہے۔
تعلیم کے مراحل
دینی تعلیم کے تین مراحل ہیں:
پہلا مرحلہ
پہلا مرحلہ ابتدائی تعلیم کا ہے جو مکاتیب کی تعلیم سے متعارف ہے۔ مکاتیب دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مکاتیب ہیں جن کے ساتھ اسکول کی تعلیم کا موقعہ فراہم ہے۔ دوسرے وہ مکاتیب ہیں جن کے ساتھ یہ سہولت نہیں ہے۔ پہلی قسم کے مکاتیب کا نصابِ تعلیم خالص دینی ہونا چاہیئے اور بہت مختصر ہونا چاہیئے۔ علومِ عصریہ کی اس میں آمیزش نہیں ہونی چاہیئے ورنہ بچوں پر ایک طرف تو تعلیم کا دوہرا بوجھ پڑے گا، دوسری طرف بے ضرورت مضامین کی تکرار ہو گی جس کا نتیجہ انتشار ذہنی کے سوا کچھ نہ ہو گا۔ اور دوسری قسم کے مکاتیب کا نصابِ تعلیم ایسا ہونا چاہیئے کہ وہ دین کی تعلیم کے ساتھ اسکول کی تعلیم کی بھی مکافات کر سکے۔ اس میں ضروری زبانوں کی تعلیم کے علاوہ علومِ عصریہ کی بھی بھرپور رعایت ہونی چاہیئے تاکہ نونہالانِ قوم، اگر ان کو آگے تعلیم کا مزید موقع نہ بھی مل سکے تو بھی وہ دینداری کے ساتھ اپنے دنیوی کام نکال سکیں۔ اور اگر مکاتیب سے نکل کر وہ بچے عصری درسگاہوں میں جانا چاہیں تو بھی ان کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
دوسرا مرحلہ
دوسرا مرحلہ ثانوی تعلیم کا ہے، اس مرحلہ میں زیادہ تر فارسی اور کچھ ابتدائی عربی پڑھائی جاتی ہے۔ اس مرحلہ میں داخل ہونے سے پہلے خود بچے کو یا اس کے اولیاء کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب اس کو کونسی راہ اختیار کرنی ہے۔ عصری تعلیم کی یا دینی تعلیم کی؟ چنانچہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اس دوسرے مرحلے میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بڑی تعداد عصری تعلیم کا رخ کرتی ہے اور بہت معمولی مقدار دینی تعلیم کا عزم کرتی ہے۔
مدارس ثانویہ کے علاوہ عصری درسگاہیں بھی فارسی بحیثیت زبان پڑھاتی ہیں۔ دونوں تعلیموں کا مشترکہ مقصد یہ ہے کہ فارسی سے اردو میں مدد لی جائے کیونکہ اردو میں فارسی کے نہ صرف لغات مستعمل ہیں بلکہ تراکیب بھی رائج ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ کلاسیکل اردو فارسی کے سانچے میں ڈھلی ہے اس لیے ادبیاتِ اردو سے کماحقہٗ استفادہ فارسی زبان کی مہارت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
اور عصری درسگاہوں اور مدارسِ اسلامیہ کی فارسی کی تعلیم کا ایک دوسرے سے مختلف مقصد یہ ہے کہ عصری درسگاہیں فارسی کو بحیثیت ایک زبان کے پڑھاتی ہیں تاکہ طلباء اس سے اقتصادی فائدہ حاصل کر سکیں، اور مدارسِ اسلامیہ میں فارسی پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ درجاتِ عربی کی جو ابتدائی کتابیں فارسی زبان میں ہیں ان سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ نیز فارسی زبان میں بزرگوں کا چھوڑا ہوا جو عظیم ورثہ ہے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ مقصد کا یہ اختلاف قدرتی طور پر دونوں کی راہیں مختلف کر دیتا ہے۔ چنانچہ عصری درسگاہوں کے فارسی نصاب کا رخ جدیدیت کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے وہی مثمر برکات ہے، اور مدارسِ اسلامیہ کے فارسی نصاب کا رخ قدامت کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے وہی مفید ہے۔ جدید فارسی پڑھا ہوا طالب علم قدیم لٹریچر نہیں سمجھ سکتا۔ الغرض نیا نصاب مرتب کرتے وقت نقطہائے نظر کا یہ اختلاف ملحوظ رکھنا ضروری ہے ورنہ شاید نیا نصاب یکساں طور پر قابل قبول نہ ہو سکے۔
تیسرا مرحلہ
تیسرا مرحلہ اعلٰی تعلیم کا ہے جسے تہائی تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تعلیم عربی میں دی جاتی ہے اور مدارسِ اسلامیہ کا اصل کام یہی تعلیم دینا ہے۔ مدارسِ اسلامیہ کے علاوہ یہ تعلیم دیگر مختلف ادارے بھی دیتے ہیں اور عصری درسگاہوں میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے۔ عربی تعلیم کی بنیادی قسمیں دو ہیں۔ لسانی اور دینی۔
بعض ادارے تو عربی کو صرف ایک زبان کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں۔ عصری درسگاہوں میں جو عربی کے ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ اسی غرض کو سامنے رکھ کر قائم کیے گئے ہیں۔ بعض بڑے مدارس میں تکمیلِ ادب عربی یا تخصص فی الادب العربی کے نام سے جو شعبے ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے۔ محض عربی زبان پڑھنے کا مقصد ظاہر ہے کہ محض اقتصادی پہلو ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ نیز اگر طالب علم چاہے تو اپنی عربی دانی سے دینی فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔
دوسرے وہ ادارے ہیں جو دین کو مقصود بنا کر عربی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ عربی زبان و ادب کے ساتھ دیگر علومِ اسلامیہ کو بھی اپنے نصاب میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ ادارے چار قسم کے ہیں:
(۱) وہ عصری درسگاہیں جن میں عربی دینیات کے شعبے قائم ہیں۔
(۲) وہ بورڈ جو عربی تعلیم کے امتحانات کا نظم کرتے ہیں۔
(۳) وہ دینی درسگاہیں جن کے پیشِ نظر دین کی تعلیم کے ساتھ کسی درجہ میں طلبہ کی اقتصادیات کا پہلو بھی رہتا ہے۔ یہ تینوں قسم کے ادارے مقصد میں متحد ہیں۔
(۴) وہ مدارسِ اسلامیہ جن کے پیشِ نظر صرف دین کے تقاضے ہیں، کوئی دوسرا مقصد ثانوی درجہ بھی اس کے پیشِ نظر نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ ادارے مقصدِ تعلیم میں پہلے تینوں قسم کے اداروں سے مختلف ہیں۔
جب ان اداروں کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں تو ایک نصابِ تعلیم سب کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ مقصد میں اشتراک یا اتحاد کے بغیر سب کو ایک روش پر ڈالنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اجتماع نقطہائے نظر کا اختلاف سامنے رکھ کر ہی نصابِ تعلیم پر نظرثانی کرے ورنہ محنت شاید رائیگاں جائے۔
نصابِ تعلیم پر نظرِثانی کیوں ضروری ہے؟
اس کے بعد اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ آخر نصابِ تعلیم پر نظرثانی کیوں ضروری ہے؟ وہ کیا اسباب و عوامل ہیں جو تبدیلی چاہتے ہیں؟ جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے پانچ وجوہ ہیں جو درج ذیل ہیں:
(۱) واقعہ یہ ہے کہ تعلیم، خواہ دینی ہو یا دنیوی، دن بدن کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ آزادی سے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ ہائی اسکول پاس کرنے والے طالب علم کی استعداد آج کے گریجویٹ سے بہتر ہوتی تھی۔ اس وقت کا کافیہ، شرح جامی پڑھا ہوا طالب علم آج کے فاضل علومِ اسلامیہ سے بہتر صلاحیتوں کا مالک ہوتا تھا۔ یہ تعلیم کی زبوں حالی زعمائے قوم، دردمندانِ ملّت اور ماہرینِ تعلیم کی نیند حرام کیے ہوئے ہے۔ یہ سب حضرات سمجھتے ہیں کہ اس ابتری کا سبب نصابِ تعلیم کی فرسودگی ہے، اس لیے جب تک نصابِ تعلیم نہیں بدلا جائے گا موجودہ صورتحال نہیں بدلے گی۔ لیکن یہ خیال کچھ زیادہ مبنی برحقیقت نہیں ہے۔ مجھے اپنے استاذ حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی قدس سرہ (سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند) کا ارشاد یاد ہے کہ
’’تعلیم میں مؤثر تین عوامل ہیں: (۱) طالب علم کی محنت (۲) استاذ کی مہارت (۳) نصاب کی خوبی۔‘‘
مگر اب طالب علم تو آزاد ہیں، ان کی کسی کوتاہی کی نشاندہی کرنا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ رہے اساتذہ تو وہ زبردست ہیں، ان کی کمی ان کو کون سمجھا سکتا ہے۔ اب رہ جاتا ہے بے زبان نصاب، چنانچہ لوگ اسے کان پکڑ کر کبھی اِدھر کرتے ہیں کبھی اُدھر، مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
(۲) زمانہ بلاشبہ ترقی پذیر ہے۔ علوم و فنون بھی ترقی کرتے ہیں اور کتابیں بھی بہتر سے بہتر وجود میں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مفید سے مفید تر کو اختیار کیا جائے تاکہ تعلیم کا بہتر سے بہتر نتیجہ نکلے۔ نصاب پر نظرثانی کرنے کی یہ وجہ نہایت معقول ہے۔ ضروری ہے کہ یہ اجتماع نصاب کی تشکیلِ جدید میں اس بات کو ملحوظ رکھے تاکہ نئی مفید چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔
(۳) زمانہ تغیر پذیر بھی ہے۔ چنانچہ زمانہ کے حالات کے ساتھ ساتھ ذہنیت بھی بدلتی ہے۔ ماضی بعید میں لوگ عقلیت پسند تھے اور معقولات سے بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ مگر اب محسوسات کا دور شروع ہو گیا ہے، ہر شخص ہر چیز مشاہدہ سے سمجھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بدلے ہوئے حالات کو پیشِ نظر رکھ کر نصابِ تعلیم میں تبدیلی کی جائے۔ نظرثانی کی یہ وجہ بھی کسی درجہ میں معقول ہے مگر اس کا اثر براہِ راست علومِ عصریہ پر پڑتا ہے۔ مدارسِ اسلامیہ میں جو علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں ان کی بنیادی قسمیں دو ہیں۔ ایک علومِ آلیہ یعنی وہ علوم جو دین فہمی کے لیے ذرائع کا کام دیتے ہیں۔ مثلاً نحو، صرف، لغت، منطق وغیرہ۔ دوسرے علومِ عالیہ یعنی وہ علوم جو مقصود بالذات ہیں جیسے قرآن کریم، احادیث شریفہ اور فقہِ اسلامی۔ پہلی قسم کے علوم میں مفید سے مفید تر کو اختیار کیا جانا چاہیے اور مدارسِ اسلامیہ میں یہ عمل برابر جاری ہے۔ مگر دوسری قسم کے علوم پر تغیر زمانہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ محکم ہیں اس لیے ان پر نظرثانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
(۴) نصابِ تعلیم پر نظرثانی کا ایک سبب وہ بھی ہے جس کی طرف اس مجلسِ مذاکرہ کے دعوت نامے میں اشارہ دیا گیا ہے یعنی فارسی اور عربی کے رائج الوقت مختلف نصابوں پر نظرثانی اس لیے ضروری ہے تاکہ فارغ شدہ حضرات کو ملک میں مناسب ملازمت مل سکے، یا وہ دوسری غیر دینی درسگاہوں میں بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ نظرثانی کی یہ بنیاد صرف ان اداروں کے نصابوں پر نظرثانی کا جواز فراہم کرتی ہے جن کا بنیادی مقصد طلبہ کی اقتصادیات ہیں، یا جن کے پیشِ نظر کسی درجہ میں اقتصادی پہلو بھی ہے۔
رہے وہ مدارسِ اسلامیہ جن کا بنیادی مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو دین کا صحیح فہم رکھتے ہوں، بالفاظ دیگر وہ قرآن و حدیث پر ماہرانہ نظر رکھتے ہوں اور علومِ اسلامیہ کی گہرائی میں پہنچ کر رموز و اسرار نکال سکتے ہوں، وہ حقیقی معنی میں دین کے نبض شناس ہوں اور ان میں دین کو ہر دور کے حالات پر منطبق کرنے کی صلاحیت ہو، یا کم از کم ایسے افراد تیار کرنا مقصد ہے جو مسلمانوں کی دینی قیادت کریں یعنی ان کی روزمرہ کی دینی ضرورت پوری کریں جسے بے باک لوگ ’’ملا گیری‘‘ کہتے ہیں، مگر وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ مسجد و مکتب کی یہ خدمت موجودہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اگر یہ خدامِ دین نہ ہوں تو مسلمانوں کی نمازِ جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ رہے۔
اور جس طرح یہ مدارسِ اسلامیہ حکومتِ وقت کے تعاون سے بے نیاز ہو کر صرف مسلمانوں کے تعاون سے کام کرتے ہیں، ضروری ہے کہ یہ فضلاء بھی حکومت کی ملازمت سے صرفِ نظر کر کے مسلمانوں کے فراہم کردہ روزگار پر قناعت کریں تاکہ وہ صحیح معنٰی میں دین کی خدمت انجام دے سکیں۔ ورنہ تجربہ شاہد ہے کہ جو فضلاء نیم سرکاری اداروں میں ملازمت کر لیتے ہیں وہ صرف عبد المال ہو کر رہ جاتے ہیں اور ان میں خدمتِ دین کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا۔
الغرض اس قسم کے مدارسِ اسلامیہ کے نصابِ تعلیم پر نظرثانی کرنے کے لیے بنیاد جواز فراہم نہیں کرتی کیونکہ ان اداروں کا مقصد ملازمت یا دنیا نہیں ہے، نہ دوسرے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ہاں مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ایک دو فیصد فضلاء ایسے ہو سکتے ہیں جو فراغت کے بعد عصری درسگاہوں کا رخ کرتے ہیں جو پوری مدتِ تعلیم میں یا تو اپنا مقصدِ زندگی متعین نہیں کر پاتے یا دنیا ہی کے مقصد سے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ان کی روشنیٔ طبع ان کے لیے آفت ثابت ہوتی ہے، یا شیطان ان کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ ایسے معدودے چند حضرات کی وجہ سے مدارسِ اسلامیہ اپنی غرض و غایت نہیں بدل سکتے۔
البتہ یہ مدارسِ اسلامیہ بھی اپنے مقصد کو پیشِ نظر رکھ کر اپنے نصاب پر نظرثانی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، مستقبل قریب میں دارالعلوم دیوبند ان شاء اللہ اس سلسلہ میں کوئی اجتماع بلائے گا اور اپنے نصاب میں ضروری اصلاح کرے گا۔
(۵) نصاب پر نظرثانی کی ضرورت بعض لوگ اس لیے بھی محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ نصاب میں بہت دقیق کتابیں ہیں جو طلبہ کی گرفت میں نہیں آتیں، ایسی کتابیں بدل کر ان کی جگہ آسان کتابیں رکھنی چاہئیں تاکہ طلباء کو نصاب سے خاطرخواہ فائدہ حاصل ہو۔ یہ بات ایک حد تک معقول ہے۔ اگر ان کتابوں کا نعم البدل وجود میں آگیا ہو تو ضرور ان کو اختیار کر لینا چاہیئے۔ لیکن اگر ان کا بدل نہ ہو تو محض دشوار ہونے کی وجہ سے ان کتابوں کو نکال دینا عقل مندی نہیں ہے بلکہ اس بات پر غور کرنا چاہیئے کہ آخر یہ کتابیں اب مشکل کیوں معلوم ہوتی ہیں؟ دشواری کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ یا تو طالبِ علم کی استعداد اس کتاب سے فروتر ہے، یا استاذ تفہیم میں ناکام ہے۔ اور دونوں ہی باتوں کا حل ممکن ہے۔
نصاب پر نظرثانی کیسے کی جائے؟
اس طویل سمع خراشی کا حاصل یہ ہے کہ فارسی اور عربی کا ملک میں کوئی ایک نصاب رائج نہیں ہے بلکہ مختلف النوع نصاب زیر تعلیم ہیں۔ نیز اداروں کے مقاصد میں بھی اشتراک یا اتحاد نہیں ہے اور نہ ممکن ہے۔ اس لیے نصاب پر نظرثانی کرنے کی بہتر صورت یہ ہے کہ ہر نقطۂ نظر کے حاملین الگ الگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور سب سے پہلے وہ اسباب متعین کریں جو تبدیلی کا سبب ہیں۔ پھر اس کی روشنی میں نصاب پر نظرثانی کریں۔ اور اگر یہ بات ممکن نہ ہو، اس وجہ سے کہ تمام نقطہائے نظر کی اس مجلس میں بھرپور نمائندگی نہیں ہے، تو پھر اس اجتماع کو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہو گا کہ اس کا دائرہ کار کیا ہو؟ اور اسی کی روشنی میں کام آگے بڑھایا جائے۔ اللھم وفقنا لما تحب و ترضٰی۔
استحکامِ پاکستان کی ضمانت
مولانا سعید احمد سیالکوٹی
’’استحکامِ پاکستان‘‘ یہ ایک جاذبِ نظر و فکر ترکیب ہے جس کے وسیع تر مفہوم میں مملکتِ خداداد پاکستان کی داخلی اور خارجی حفاظت و امن کی کفالت ہے۔ اس پُرمغز عبارت کے ناجائز استعمال سے یہ ایک پُرفریب ترکیب بن گئی کیونکہ وطنِ عزیز میں اربابِ حکم کی طرف سے قوتِ اقتدار ہمیشہ پاکستانی عوام کی خدمت و خوشحالی اور وطن کے داخلی اور خارجی استحکام کے بجائے حکمران فرد یا حکمران پارٹی کے طولِ اقتدار اور ذاتی اغراض و مصالح کی تکمیل و حصول کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔
استحکامِ پاکستان درحقیقت ایک عظیم مقصد ہے جو ہر محبِ وطن پاکستانی کی نہیں بلکہ امتِ اسلامیہ کے ہر فرد کی، پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی، تمنا و آرزو ہے۔ استحکامِ پاکستان کی درست تشریح اور اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ استحکام سے مراد تو داخلی امن، اخوت و محبت، وحدتِ قومیت کا ایسا تصور جو علاقائی اور لسانی تعصبات سے پاک ہو اور خارجی طور پر وطن کی سرحدوں کا محفوظ و مامون ہونا ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بالکل واضح اور مختصر ہے اور وہ اس نظریہ کا عملی نفاذ ہے جس کے لیے پاکستان معرضِ وجود میں آیا۔
تحریکِ پاکستان کے شریک زعماء کے وردِ زبان یہی کلمہ تھا ’’پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الٰہ الّا اللہ‘‘۔ یہ عظیم کلمہ بندوں اور ان کے رب کے درمیان ایک عہد ہے جس کا تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں شریعتِ اسلامیہ کا مکمل نفاذ ہو۔ یہ اہلِ پاکستان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا اقرار ہے اور ان کا قومی فریضہ ہے جس کی رو سے ان کے ملک میں کسی اجنبی نظامِ حیات کی ہرگز ہرگز درآمد کرنے کی اجازت نہیں نہ اس کی گنجائش ہے، کہ ان کے پاس ان کے رب کا بنایا ہوا کامل و مکمل نظامِ حیات، جو بشری نقائص سے پاک و صاف ہے، موجود ہے۔ بلکہ قومی طور پر ان کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نظام کے باغی کو پاکستان کا باغی قرار دیں اور اجنبی نظام کو درآمد کرنے والے کو ملک و قوم کا دشمن قرار دیں جو ان کے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا اور بنیادوں کو ہلانا چاہتا ہے، ان کی قومی وحدت کو پارہ پارہ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ شریعتِ مطہرہ کا مکمل نفاذ ہی بانیانِ پاکستان اور مجاہدینِ آزادی کا اصل ہدف اور ان کے جہاد اور تحریک کی روح تھا۔ اسی اعلیٰ اور متحد مقصد کی خاطر بنگالی، سندھی، بلوچی، سرحدی اور پنجابی یکجان ہوئے اور ہمارے عقیدہ و ایمان کے لاکھوں بھائیوں نے ہجرت کا عظیم عمل سرانجام دیتے ہوئے مال و جان کی قربانی دی۔ سب کے دلوں کی دھڑکن ’’لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ‘‘ تھی اور یہ مہاجرین و انصار ایک ایسے وطن میں ایک قوم بن کر بس گئے جسے وہ اسلام کا قلعہ اور عالمگیر عدلِ اسلامی کا مظہر دیکھنا چاہتے تھے۔
تقسیم ہندوستان سے کچھ اور پیچھے چل کر دیکھیں تو انگریزی حکومت کے خلاف جہادِ آزادی کرنے والے مسلم مجاہدین کا مقصود بھی اسی برصغیر کے خطہ میں ایک ایسی سرزمین کا حصول تھا جو ہر غیر اسلامی تسلّط سے پاک ہو، اس ارضِ پاک میں خدا رسول کی پاک شریعت کا نفاذ ہو۔ الحمد للہ کہ قیامِ پاکستان کی تحریک اور انگریزی اور ہندو تسلط سے آزادی حاصل کرنے والے مجاہدین کی کوششیں بارآور ہوئیں اور برصغیر میں ارضِ پاک مملکتِ خداداد پاکستان معرضِ وجود میں آگئی۔ خدائے ذوالجلال نے مختلف افراد اور جماعتوں کو اس خطۂ پاک میں زمامِ اقتدار دے کر اس امانت کو ان کے سپرد کیا، اور یہ ان سب کے لیے خدائی آزمائش تھی کہ وہ اس میں کیسے تصرف کرتے ہیں؟
ہر صاحبِ اقتدار خدا کے نام پر حلف اٹھا کر اس ملک کے استحکام کے وعدہ پر قسم اٹھاتا اور اقتدار سنبھالتا رہا۔ ان اربابِ حکم کے ہاتھوں شریعت خداوندی کا نفاذ ہو جاتا تو نہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بدعہدی ہوتی، نہ مجاہدینِ آزادی سے بے وفائی، نہ قومی وحدت کو دھچکا لگتا، اور نہ ہی مشرقی پاکستان کے انفصال کا عظیم المیہ پیش آتا، نہ صوبائی تعصبات اور لسانی فسادات جنم لیتے۔ متحدہ ہندوستان کے وقت آخر اسی نظریہ نے ہی سب کو اخوت کے رشتہ میں جوڑا تھا۔ ہماری قومی وحدت اور ہمارے وطن کے استحکام کا ضامن اور عظیم پاکستان کی روح و جاں یہی نظریہ تھا اور ہے۔ اس سے انحراف اور اربابِ حکم کی خدا رسول کے ساتھ عہد شکنی کے نتیجہ میں ہم نہ صرف برکاتِ سماویہ و ارضیہ سے محروم ہوئے بلکہ اپنی قومیت اور شناخت اور خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ ارشاد ربانی ہے:
’’تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو فراموش کر بیٹھے اور جس کی سزا ان کو خود فراموشی کی صورت میں ملی۔‘‘
جس کا لازمی نتیجہ داخلی خلفشار اور دیگر وہ حالات ہیں آج جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔۔۔ ہمارے اربابِ حکم محض اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ’’استحکامِ پاکستان‘‘ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے مراد صرف ان کی ذات یا ان کی حکمران جماعت کو تحفظ ہوتا ہے۔ اس کے لیے مختلف قوانین بھی وضع کرتے ہیں اور ملکی تحفظ کی آڑ میں اپنی کرسی اور مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں۔ ان کی کوششیں صرف اپنی خدمت اور چند افراد کے ساتھ تعاون تک منحصر ہو جاتی رہی ہیں۔
اربابِ حکم کے سامنے خدا تعالیٰ کی شریعت سے انحراف ہوا، اجنبی نظریات کا پرچار ہوا بلکہ بعض تو خود اس کی دعوت کے علمبردار بن گئے، ملک میں اندرونی خلفشار ہوا، بیرونی طور پر اس کی حدود کو غیر محفوظ و مامون کہہ دیا گیا، اور خود حکمران بھی اس عملِ شر میں شریک پائے گئے۔ اگر شریعت مطہرہ کا نفاذ ہوتا، اسلامی عالمگیر عدالت کے تحت ملک کی سیاست و معاملات کو طے کیا جاتا، اندرون ملک قانونِ خداوندی اور حدود اللہ کی حفاظت کی جاتی، تو پاکستان ایک مثالی رفاہی مملکت بنتا، نہ معاشی پریشانی نہ داخلی خلفشار دیکھا جاتا۔ کیونکہ اسی کلمہ مبارک ’’لا الٰہ الّا اللہ‘‘ نے انہیں متحد کیا تھا اور مشرق و مغرب ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے۔ یہی کلمہ ان کے داخلی و خارجی، اقتصادی اور سیاسی تحفظ کا یقیناً ضامن تھا اور آج بھی ہے۔
اہلِ وطن عزیز اور اربابِ حکم آج بھی خدا تعالیٰ سے سابقہ گناہوں پر معافی مانگ کر تجدیدِ عہد کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اس خطۂ زمین پر صرف اور صرف اسی کی قائم کردہ شریعت کا مکمل نفاذ اس کو صحیح معنوں میں پاکستان (پاک سرزمین) بنا سکتا ہے۔ ان شاء اللہ اقامتِ شریعت کے سبب ہی ہم آسمانی اور زمینی برکات سے مستفیذ ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے:
’’اگر یہ لوگ خدا کی نازل شدہ شریعت کو قائم کرتے تو آسمان و زمین کی نعمتوں سے مالامال ہوتے۔‘‘
اگر کوئی خدائی وعدہ پر یقین نہ کرے تو اس تناظر میں ہم سعودی عرب کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں جہاں کا امن مشرق و مغرب میں مثالی ہے اور جس کی رفاہیت کی نظیر کسی ملک میں نہیں ہے۔ ذرا ماضی کو پلٹ کر دیکھیں تو موجودہ حکومت سے پہلے جزیرہ عرب میں بداَمنی کا دور دورہ تھا، غربت و افلاس کا یہ عالم کہ چند ٹکوں کی خاطر حجاج و زائرین کی جان تک ضائع کر دی جاتی تھی بلکہ بقول شخصے اگر کسی کو گولی کا نشانہ بنانے کے بعد اس سے مال نہ ملتا تو افسوس اس بات پر ہوتا کہ ایک گولی کا خسارہ ہو گیا۔ مگر اللہ کی حدود کے قیام اور شریعتِ مطہرہ کے نفاذ کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور اقتصادی خوشحالی اور داخلی امن و امان کا یہ عالم کہ دنیا کی تمام متمدن اور ترقی یافتہ قومیں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ قانونِ خداوندی ہی اللہ کی سرزمین میں امن و امان کا واحد ضامن ہے۔ کیونکہ سعودی عرب میں مغرب و مشرق کی دیگر قوموں کے مقابلہ میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے جس کا مشاہدہ ہر حاجی، زائر اور یہاں پر مقیم ہر شخص کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور اپنے اربابِ حکم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیوں ہمارے پاک وطن کو استعماری نظامِ حیات کی نحوستوں سے نجات نہیں دی جاتی؟ کیوں اسلام کے عادلانہ نظام کو اپنا کر ہمیں برکاتِ ارض و سماء سے مستفیض نہیں ہونے دیا جا رہا؟
پاکستان کے محبِ اسلام عوام اور ان کے پیارے دین کے نفاذ کے درمیان جو لوگ آڑ ہیں وہ صرف خدا رسول کے ہی نہیں بلکہ پاک سرزمین اور اس کے مخلص عوام کے بھی دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم ایک بنے، یہ قوم خوشحال ہو، یہ قوم خدا رسول کی محبوب بن کر اس کے خزانوں کی وارث بنے، اور ان کے ملک میں داخلی استحکام ہو اور اقتصادی رفاہیت ان کو میسر آئے۔
استحکامِ پاکستان کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ داخلی امن اور اقتصادی خوشحالی کی ضمانت اور کفالت صرف اور صرف نظریۂ پاکستان کے عملی نفاذ میں پنہاں ہے۔ اب خارجی طور پر ملک کے سرحدوں کی حفاظت اور اطراف کے اعداء سے ملک کو مامون و محفوظ کرنے کا مسئلہ ہے جو استحکامِ وطن کا لازمی جزء ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتِ مسلمہ کی عظمت جہاد کو قرار دیا۔ اس جذبہ کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے اعداءِ اسلام نے بہت کوششیں کیں، جھوٹے نبی تک کو جنم دیا کہ امت کو شیطانی وحی کے ذریعے یہ درس دیا کہ جہاد کو بھلا دیں۔ اس دجل کا توڑ الحمدللہ اہلِ اسلام نے پورے طور پر کیا اور ادھر حق تعالیٰ شانہٗ نے اس دور میں جہادِ افغانستان کی شکل میں امتِ اسلامیہ کو عموماً اور پاکستانی قوم کو خصوصاً اس درس کی علمی مشق کا موقع فراہم کیا تاکہ اعداءِ اسلام پر اپنی عظمت کی دھاک بٹھانے کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین کے استحکامِ خارجی کا عمل بھی مکمل کیا جا سکے۔ لہٰذا ایک سرحد پر اپنے افغان بھائیوں کے جہاد میں اشتراک اور ان کی مکمل کامیابی تک ہمارا تعاون اس جہت سے وطنِ عزیز کے خارجی استحکام کے مترادف ہے۔ جو فرد یا جماعت اس فریضہ میں کوتاہی کرتا ہے وہ اگر ایک طرف ایک اہم دینی فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے ایک اہم دینی فریضہ کا تارک یا منکر ہے تو دوسری طرف پاکستان کے استحکام کا بہی خواہ نہیں۔
ملک کے خارجی استحکام کا تعلق ایک سمت سے جہادِ افغانستان ہے تو دوسری طرف مسئلہ کشمیر ہے۔ ہمارے عقیدہ و ایمان کے کشمیری بھائی جو عرصۂ دراز سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں جنہوں نے اپنی حریت کی تحریک کا آغاز اس جذبہ کے تحت کیا ہے کہ بقائے زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ عملی تعاون حتٰی کہ وہ اپنے فطری انسانی حقِ حریت کو پا لیں، اہلِ پاکستان کا ان حریت پسندوں سے تعاون اور ان کے جہاد میں اشتراک استحکامِ پاکستان کی ہی ایک کڑی ثابت ہو گا، ان شاء اللہ العزیز۔
الغرض اندرون ملک شریعتِ مطہرہ کا نفاذ اور بیرون ملک اپنے مظلوم اور مجاہد بھائیوں سے تعاون امتِ اسلامیہ کی وہ خدمت ہے جس کے ثمرات سے پوری امتِ اسلامیہ کا سر اگر فخر سے بلند ہو گا تو سب سے پہلے ’’استحکامِ پاکستان‘‘ جیسے مقدس الفاظ، پُرمغز عبارت، اور وسیع تر مفہوم کی حامل ترکیب کی درست شرح کی تکمیل بھی ہو گی۔ خوش قسمت ہے وہ حکمران شخصیت، یا حکمران جماعت، یا اربابِ سیاست جن کے ذریعے نظریۂ پاکستان کی حفاظتِ عملی ہو۔ اور بہت ہی مبارک ہاتھ ہیں وہ ہاتھ جن کے ذریعے شریعتِ مطہرہ کا مکمل نفاذ ہو۔ تاکہ خدائے ذوالجلال سے کیا ہوا عہد پورا ہو اور وہ ذاتِ عالی اس کے بدلہ میں اپنے وعدہ کو پورا فرماتے ہوئے ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں، اور ہمارے مجاہدینِ آزادی اور تحریکِ پاکستان میں شریک زعماء کی ارواح مطمئن ہوں، اور قربانی دینے والوں اور وطن کے بہی خواہوں کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو اور وہ امن و امان، رفاہیت اور وحدتِ ملّی کا مشاہدہ کر لیں۔
’’ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم‘‘ اگر تم اللہ کے دین کا ساتھ دو گے تو وہ ذاتِ عالی تمہاری نصرت کرے گی اور تمہارے قدم جما دے گی۔ اور اگر تم انحراف کرو گے تو تمہارے عوض ایسی قوم لے آئے گی جو تمہاری طرح نہ ہو گی۔
کیا حضرت عیسٰیؑ کی وفات قرآن سے ثابت ہے؟
حافظ محمد عمار خان ناصر
جب روح اللہ، کلمۃ اللہ حضرت عیسٰی المسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کسی جماعت، حلقے یا مجلس میں ہوتا ہے تو ان کی حیات و وفات کی متنازعہ حیثیت اور اس سے متعلقہ بحث طلب امور کا زیربحث آجانا ایک لازمی امر ہے خصوصًا یہ کہ کیا حضرت مسیحؑ نے رفع الی السماء سے قبل وفات پائی یا کہ نہیں۔ چنانچہ یہ مسئلہ عیسائی اور مسلم حضرات کے درمیان ہمیشہ سے متنازعہ ہے اور تب تک رہے گا جب تک کہ (اہلِ اسلام کے عقیدہ کے مطابق) حضرت عیسٰیؑ نزول کے بعد صلیب کو نہیں توڑ دیتے (بخاری جلد اول ص ۴۹۰ باب نزول عیسٰی ابن مریمؑ)۔
ازروئے قرآن حضرت عیسٰیؑ کی وفات قبل از رفع ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ قرآن پاک نے اس کی شدت سے نفی کی ہے۔ چنانچہ سورہ المائدہ میں ہے
وَمَا قَتَلُوْہُ وَمَاصَلَبُوْہُ
یعنی انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ سولی دی۔
جبکہ عیسائی پادری صاحبان کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی مندرجہ ذیل آیت سے عیسٰیؑ کی وفات قبل از رفع ثابت و متحقق ہے
اِذْ قَالَ اللہُ یَا عِیسٰی اِنّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسٰیؑ میں تجھے پورا (یعنی روح و بدن سمیت) لینے والا ہوں یعنی تجھے اپنے آسمان کی جانب اٹھانے والا ہوں۔
عیسائی پادری ’’متوفی‘‘ سے حضرت عیسٰی علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں لیکن ان کا یہ دعوٰی درست نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے قطعًا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسٰیؑ نے آسمان پر جانے سے قبل موت کا مزہ چکھا بلکہ علامہ آلوسیؒ (المتوفی ۱۲۷۰ھ) کی تصریح ہے کہ
فالکلام کنایۃ عن عصمتہ من الاعداء۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۵۸)
’’پس کلام کنایہ ہے اس سے کہ وہ دشمنوں (کی سازش) سے بچ گئے۔‘‘
اور علامہ نیشاپوریؒ ’’غرائب القرآن‘‘ میں آیت توفی کے تحت فرماتے ہیں:
یا عیسٰی انی متوفیک الی متمم عمرک و عاصمک من ان یقتلک الکفار الآن بل ارفعک الی سمائی واصونک من ان یتمکنوا من قتلک۔ (ج ۳ ص ۲۰۶)
’’اے عیسٰی! بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں یعنی تیری عمر کو پورا کرنے والا ہوں اور تجھے اس سے بچانے والا ہوں کہ کفار اب تجھے قتل کر دیں بلکہ میں تجھے اپنے آسمان کی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے بچاؤں گا اس سے کہ یہ (یہودی) تجھے قتل کر سکیں۔‘‘
صاحبِ کشاف (زمحشریؒ) اور صاحبِ مدارک کی رائے میں متوفی بمعنی مستوفی اجلک کے ہے۔ چنانچہ ان دونوں تفسیروں میں صراحت ہے کہ:
’’ممیتک حتف انفک لا قتیلا بایدیہم۔ (کشاف ج ۱ ص ۳۶۶ و مدارک ج ۱ ص ۲۵۵)
’’میں تجھے تیری طبعی موت ماروں گا، ان کے ہاتھوں تو قتل نہ ہو گا۔‘‘
قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ اس مسئلہ پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ
والظاھر عندی ان المراد بالتوفی ’’ھو الرفع الی السماء بلا موت‘‘۔ (مظہری ج ۲ ص ۵۶)
’’میرے نزدیک یہی ظاہر ہے کہ توفی سے مراد آسمان کی طرف بغیر موت کے چڑھ جانا ہے۔‘‘
امام قرطبیؒ کی رائے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسٰیؑ کو بغیر وفات اور نیند کے اٹھا لیا (قرطبی بحوالہ روح المعانی)۔
قدماء مفسرینؒ میں سے امام ابن جریر طبریؒ اس آیت کے تحت متعدد اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں:
واولی ھذہ الاقوال بالصحۃ عندنا قول من قال معنی ذلک انی قابضک من الارض ورافعک الی۔ (طبری ج ۳ ص ۲۰۴)
قرآن کریم کے علاوہ احادیث و روایات سے بھی حضرت عیسٰیؑ کا بغیر موت کے عروج ثابت ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی روایت نقل کرتے ہیں کہ
قال رسول اللہ للیھود ان عیسٰی لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامۃ۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۵۸)
’’رسول اللہؐ نے یہود سے فرمایا کہ بے شک عیسٰیؑ نہیں مرے اور بے شک وہ تمہاری طرف قیامت کے دن سے پہلے لوٹنے والے ہیں۔‘‘
الغرض علماء نے توفی کے مختلف معانی بیان کیے ہیں لیکن کسی کے قول سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسٰیؑ نے قبل از رفع وفات پائی۔ ہاں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت تفاسیر میں ملتی ہے جس میں متوفیک کا معنی ممیتک کیا گیا ہے لیکن علامہ آلوسیؒ اور علامہ نیشاپوریؒ نے اس کو ’’قیل‘‘ کے ساتھ نقل کیا ہے جس سے اس کا ضعف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں اس صورت میں بھی کوئی قباحت لازم نہیں آتی کیونکہ ضروری نہیں کہ موت رفع سے پہلے متحقق ہو حتٰی کہ حضرت قتادہؒ کی رائے یہ ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور تقدیر یوں ہے:
انی رافعک الی و متوفیک یعنی بعد ذلک۔
یہ قول تفاسیر میں منقول ہے (دیکھئے روح المعانی ج ۱ ص ۱۵۸ و درمنشور ج ۲ ص ۳۶ و ابن کثیر ج ۱ ص ۳۶۶)۔ اور یہ قول عین عرب کے محاورے اور لغت کے مطابق ہے جیسا کہ نحو اور اصول فقہ کی معتبر کتابوں میں تصریح ہے کہ ’’واو‘‘ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ اس جگہ کافیہ کی عبارت مع شرح ملّا جامی کے مرقوم ہوتی ہے:
فالواو للجمع مطلقا لا ترتیب فیھا فقولہ لا ترتیب فیھا بین المطعوف والمطعوف علیہ بمعنی انہ لا یتمم ھذا الترتیب منھا وجودًا او عمدًا۔
اور اصولِ فقہ کی مشہور کتاب نورالانوار میں ہے:
فالواو لمطلق العطف من غیر تعرض لمقازتہ ولا ترتیب یعنی ان الواو لمطلق الشرکۃ۔
اسی طرح ’’المنجد‘‘ میں جو کہ ایک کیتھولک عیسائی کی تصنیف ہے لکھا ہے ’’معناھا مطلق الجمع‘‘۔
اس کے علاوہ متن متین اور حسامی کے علاوہ متعدد تفاسیر میں بھی یہ قاعدہ قرآنی بیان کیا گیا ہے اور رضی میں بادلائل بحث کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ’’متوفیک و رافعک‘‘ میں اگر توفی معنی موت لیا جائے تو بھی اس کا رفع سے پہلے ہونا ضروری نہیں ہے اور اس سے رفع الی السماء سے پہلے حضرت عیسٰیؑ کی وفات پر استدلال درست نہیں ہے۔ لیکن اس معقول تاویل کے باوجود مفسرینؒ نے اس کو پسند نہیں فرمایا جیسا کہ اوپر گزر چکا کہ آلوسیؒ اور نیشاپوریؒ نے اس کو ’’قیل‘‘ کے لفظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو اس طرح یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن پاک سے حضرت عیسٰی علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہے اور جو لوگ مذکورہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن پاک نے ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے:
مَا لَھُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ۔
اقبالؒ — تہذیبِ مغرب کا بے باک نقاد
پروفیسر غلام رسول عدیم
مہینوں اور سالوں میں نہیں صدیوں اور قرنوں میں کسی قوم میں کوئی ایسی شخصیت جنم لیتی ہے جس کے لیے نسلِ انسانی عمروں منتظر رہتی ہے اور جب وہ شخصیت منقہ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہے تو صدیوں اس کی یاد ذہنوں کو معنبر رکھتی، سوچوں کو اجالتی، فکر کی آبیاری کرتی اور دلوں کو گرماتی اور برماتی رہتی ہے ؎
عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات
تاز بزمِ عشق یک دانائے راز آید بروں
یہاں پیغمبرانِ الٰہی خارج از بحث ہیں کہ وہ چیدہ اور برگزیدہ ہوتے اور منصبِ اصطفاء و اجتباء پر فائز ہوتے ہیں، وہ از خود دعوتِ فکر و عمل لے کر نہیں اٹھتے مگر ان کے پاس اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک بنا بنایا پروگرام ہوتا ہے اور وہ خود بھی بنے بنائے آتے ہیں، اپنی ریاضت و اکتساب سے نہیں بنتے، بھیجنے والے کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کس خطہ میں کن لوگوں کی طرف اور کس زمانے میں بھیجے، وہ ایک طرف مامور من اللہ ہوتے ہیں تو دوسری طرف آمر بامر اللہ، خالق کے مطیع، مخلوق کے مطاع، خلیق کے قائد، خالقِ کائنات کے منقاد۔ بات ان شخصیات کی ہو رہی ہے جو الٰہی پروگرام ان معنوں میں رکھتے جن معنوں میں فرستادگانِ الٰہی رکھتے ہیں بلکہ وہ جنہیں خالقِ کائنات دل و دماغ کی بہترین صلاحیتوں سے نوازتا ہے اور پھر ان سے خلق کی اصلاح و فلاح کا کام لیتا ہے۔ ان کا علمی بلوغ، ان کی فکری جولانیاں، ان کی مثبت اور توانا سوچ ایک عالم کو گمراہی اور عملی بے راہروی سے نکال کر جادۂ مستقیم پر لگا دیتی ہے۔
علامہ اقبالؒ کی عظیم شخصیت ایسے ہی اساطینِ عالم میں سے ایک ہے جو درماندہ پا بہ گل ہجوموں کو منظم گروہوں کی شکل دے کر جادہ پیمائی کا شعور بخشتے ہیں۔ اقبال نے بھی اس بلند آہنگی سے اور سوزِ دروں سے حدی خوانی کی۔ صدیوں کے مسافر لمحوں میں منزل شناس ہوتے نظر آئے۔ یہ وہ کارواں تھا جو بطحا کی وادی سے نکلا اور اطرافِ عالم میں ہر چہار جانب پھیل گیا۔ حدودِ برصغیر میں پہنچا تو آٹھویں صدی عیسوی کا آغاز ہو چکا تھا۔ آٹھویں صدی عیسوی سے لے کر انیسویں صدی عیسوی تک برصغیر کی سیادت و قیادت اس جاں سپارگروہ کے ہاتھ میں رہی۔ گردش ایام اور زندگی کے نشیب و فراز نے اسے کبھی فرمانروائی کی مسندِ بالا پر بٹھایا تو کبھی پستی و زوال کے عمیق غاروں میں دھکیل دیا۔
۷۱۳ء میں محمد بن قاسمؒ نے سندھ و ہند میں اسلام کا پھریرا لہرا کر عقائد باطلہ اور توہمات میں جکڑے ہوئے سماج کو فکر و نظر کی آزادی بخشی۔ بعد ازاں منصورہ اور ملتان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اگرچہ اس کا اثر و نفوذ زیادہ دور تک نہ پھیل سکا اور وہ برصغیر کے شمال مغربی حدود و ثغور سے آگے نہ بڑھ سکی تاہم تین سو سال بعد روشنی کا ایسا سیلاب امڈا کہ شمالی دروں کی راہ آنے والے غزنیوں اور غوریوں نے اس کفرستانِ ہند میں غلغلۂ توحید سے دیومالائی اور اساطیری ضعیف الاعتقادی کا تاروپود بکھیر کر رکھ دیا۔
جب ۱۲۰۶ء میں برصغیر میں حکومتِ اسلامیہ کے اصل بانی سلطان قطب الدین ایبک نے دہلی کو مستقل مستقر بنا کر گجرات، کاٹھیاوار، کالنجر اور بنگال تک یلغار کی تو اس امر کا یقین ہو گیا کہ اب صدیوں تک برصغیر میں اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا۔
۱۷۰۷ء میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اگرچہ ۱۸۵۷ء تک کوئی ڈیڑھ سو برس تک اسلامی حکومت قائم رہی مگر فی الجملہ یہ دور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے انحطاط اور تنزل کا دورِ نافرجام تھا۔ سیاسی افراتفری، معاشرتی ناہمواری اور اقتصادی بدحالی نے مسلمانوں کی عظمت کو گئے دن کا قصہ بنا کر رکھ دیا۔ سات سمندر پار سے آنے والے سفید فام مگر سیاہ دل فرنگی کی دسیسہ کاریوں نے مسلمان سے حمیت و غیرت چھین کر اسے تملق و مداہنت کا خوگر بنا دیا۔ اس دور میں بعض دھڑکتے دل والے مصلحین نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا، مسلمانوں کو ان کی اسلامی عصبیت سے آگاہ کیا، ان میں حضرت شاہ ولی اللہؒ، سید احمد بریلویؒ، شاہ اسماعیل شہیدؒ، سر سید احمد خانؒ، حاجی شریعت اللہؒ، اور تیتومیرؒ جیسے جہد آمادہ پیکرانِ حریت نے فضا میں ایمان و ایقان کی سرمستیاں بکھیر دیں اور مسلمانانِ برصغیر کو خودشناسی کا درس دیا۔
لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس حد تک پستیوں میں اتر چکے تھے کہ اب ان کا تنزل کی اتھاہ گہرائیوں سے ابھرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی نے مسلمانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یوں بیسویں صدی کے آتے آتے مسلمان اس درکِ اسفل تک پہنچ چکے تھے کہ انہیں انگریزی استیلاء سے نجات دلانے کے لیے اعجازِ مسیحائی رکھنے والی ایسی سحر اثر شخصیت کی ضرورت تھی جو اسے اپنی شناخت کرا سکے۔ نہ صرف عرفانِ ذات بخشے بلکہ یہ باور کرائے کہ تم انہیں اسلاف کے وارث ہو جنہوں نے قیصر و کسرٰی کی عظیم سلطنتوں کو پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کوہ و صحرا لرزتے تھے، جو ان بلاخیر طوفانوں سے بڑھ کر تھے جن سے دریاؤں کے دل ہل جاتے تھے، اور جن کی یلغاروں سے کوہ پائرنیز کے اس پار ایسا ارتعاش پیدا ہوا کہ مدتوں یورپی اقوام اس کے اثرات محسوس کرتی رہیں۔
اب وقت آن پہنچا تھا کہ وہ عیسٰی نفس غلاموں کے لہو کو گرمائے اور کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا کر دے۔ چنانچہ بیسیوں صدی نے بڑھ کر اس مسیحا نفس کا استقبال کیا۔ سچ ہے کہ جب تاریکیاں گہری ہو جائیں تو ٹمٹماتا ہوا دیا بھی قندیل بن کر جگمگاتا ہے لیکن اگر واقعی فانوس روشن کر دیا جائے تو اس کی امواجِ نور سے یقینًا تاریکیاں کافور ہو جائیں گی اور پورا ماحول نور میں نہا جائے گا۔ وہ فانوس فروزاں ہوا، تیرگی چھٹی، وہ رجلِ عظیم آیا، اس نے ناقۂ بے زمام کو سوئے قطار کھینچا۔ انبوہ خفتہ کو اپنی بانگِ درا سے جگایا، عروق مروۂ مشرق میں زندگی کا خون دوڑا دیا۔ اس شان سے صورِ اسرافیل پھونکا کہ صدیوں کی مردہ روحیں زندگی کی توانائیوں سے سرشار ہو کر انگڑائیاں لینے لگیں، کارواں کو پھر سے منزل کی طرف گامزن ہونے کا حوصلہ ملا۔
اس رجل رشید کی بوقلموں شخصیت میں یوں تو ایک بیدار مغز سیاستدان کا تدبر، ایک حلیم و بردبار انسان کا جگر، ایک عظیم و جلیل شاعر کا تنوع، اور ایک عظیم تر فلسفی کا ماورائی ادراک تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی حقیقی وجہ مجدد شرف اور اصلی اثاثہ وہ اندازِ نظر ہے جس نے اسے ذاتی حیثیت سے اٹھا کر کائناتی فکر کا مالک بنا دیا۔ اس نے ایک خوابِ غفلت میں سوئے ہوئے ہجوم کو جگایا اور منظم جماعت کی صورت دے دی۔ قوم کا وہ تصور دیا جس سے مغرب نابلد تھا ؏
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمیؐ
اقبال سے پہلے سرسید احمد خان کے عظیم رفقاء میں حالی نے قومی سوچ کی نیو اٹھائی مگر حالی کی آواز میں اس قدر دھیماپن تھا کہ اکثر لوگوں نے سنی اَن سنی کر دی۔ بلاشبہ اس آواز میں سوز تھا مگر گھن گرج نہ تھی، خلوص تھا مگر محدودیت کے ساتھ دردمندی تھی۔ مگر نوحہ و بکا کی لے میں یوں حالی کی قومی فکر مایوسیوں کی نذر ہو گئی۔ وہ ایک گہرے کنویں کی طرح تھی جو کبھی تہہ کے چشموں کے ابلنے سے جوش تو مارتا ہے مگر اس میں سمندر کی طغیانی اور تلاطم انگیز موجوں کی روانی نہیں آسکتی۔ نتیجہ یہ نکلا حالی کی گریہ و زاری یاس خیزیوں تک آ کر رہ گئی۔ تاہم یہ شیونِ قومی اکارت نہیں گیا۔ اقبال نے حالی کی رکھی ہوئی نیو پر ایک فلک بوس ایوان کھڑا کر دیا۔ حالی علومِ جدیدہ سے ناواقفیت کی بنا پر گہرائی کے باوجود گیرائی سے محروم رہے۔ آفاقی وسعت کے فقدان کے باوجود اقبال نے حالی کو بھرپور خراجِ تحسین پیش کیا ؎
طوافِ مرقد حالی سزد ارباب معنی را
نوائے او بجانہا افگند شورے کہ من دانم
حالی کے زمانے میں اس شور کو زیادہ نہیں سنا گیا مگر اقبال نے نوائے حالی سے تحریک پا کر فضا میں غلغلہ اندازی کا سامان پیدا کر دیا۔
اقبال کے مجدد شرف کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اس نے مشرق و مغرب کو پڑھا، پڑھا ہی نہیں خوب کھنگالا، اس قدر جانچا اور آنکا کہ اپنی مشرقیت کو مغربیت کی زد میں نہ آنے دیا۔ پچھلی دو صدیوں سے عمومًا اور عصرِ حاضر میں خصوصًا مغرب نے اپنے مادی استیلاء اور ظاہری وسائلِ حیات سے پوری دنیا کو خیرہ کر دیا ہے۔ جدید سائنسی پیشرفت اور ٹیکنالوجی نے ہر سطح بیں کے دل میں مغربیت کے علمی بلوغ و نبوع کا نقش جما دیا۔ جو شخص ایک بار لندن کی ہوا کھا آیا فرنگی فکر کا پرستار پایا گیا۔ جس نے پیرس کی ہموار اور گداز سڑکوں پر گھوم پھر لیا اسے دلّی کے وہ کوچے اجنبی سے لگنے لگے جن کے بارے میں شاعر نے کہا ؎
دِلّی کے نہ تھے کوچے اوراقِ مصوّر تھے
جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی
جس شخص نے نیویارک کی ایوے نیوز میں مٹر گشت کر لیا اس نے جانا گویا وہ فردوسِ بریں کی سیر کر آیا۔ اب لاہور کی ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے اسے الجھن محسوس ہونے لگی۔ زبانِ حال ہی سے نہیں زبانِ قال سے پکار اٹھا ؏
افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند
مگر زمانہ معترف ہے کہ اقبال ۱۹۰۵ء میں انگلستان گیا، کیمبرج کے محققینِ عصر اور نامورانِ دہر سے خوشہ چینی کی، ان عمائد علم و فضل سے استفادہ کیا جو علوم و فنون میں ماہرانہ دستگاہ ہی نہیں سند کا درجہ رکھتے تھے۔ جرمنی پہنچا، تحقیق و تدقیق اور علم و حکمت کی پرخار وادیوں میں آبلہ پا دیوانوں کی طرح قدم فرسائی کی۔ بلادِ فرنگ میں سہ سالہ قیام کے دوران میں بلا کی سردی میں بھی سحرخیزی کا التزام رکھا ؎
زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی
نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سحر خیزی
ایک طرف علم و آگاہی کے جواہر ریزے سمیٹے تو دوسری طرف مغرب کے تمدن کو محققانہ و ناقدانہ نگاہ سے دیکھا۔ سطح بینوں کی طرح نہیں، اندر جھانک کر ان کے آدابِ زیست کا بغور جائزہ لیا۔ ان کے آدابِ معاشرت کے محاسن و معائب پر نگاہ ڈالی، ان کی سیاسی فکر پر پہروں غور کیا، فرنگی اقوام کی مذہبی سطحیت اور دین بیزاری کو آنکا اور پرکھا۔ ان کے اقتصادی نظام کا بغور مطالعہ کیا، غرض ان کے تمدنی نظام کے ایک ایک جزئیے کا استیعابًا مطالعہ کیا۔
اب وہ موقع پرست اور بیرونِ در تک رہنے والا نہ تھا، درونِ در کے ہنگاموں سے بھی باخبر تھا۔ لہٰذا اس کے سینے میں اس تمدن کے خسارت اندوز پہلوؤں کے خلاف لاوا پکتا رہا۔ فرنگی حضارت اور مغربی تہذیب جس پر مغرب کو خود بہت ناز تھا اور اوپری نظروں سے دیکھنے والے اہلِ مشرق بھی اس پر تحسین کے ڈونگرے برساتے تھے، اقبال کی نظر میں یہ ملمع کاری تھی۔ اس نے کئی موقعوں پر اس تہذیب کے خلاف گہرے معاندانہ جذبات کا اظہار بھی کیا۔
سیاسی فکر میں اقبال نے یورپی تصورِ قومیت کو نہایت ناپسندیدہ اور مکروہ پایا، اس نے اس تصور کو بنی آدم کے حق میں زہرناک خیال کیا۔ چنانچہ پانچ چھ سال بعد دنیا نے کھلی آنکھوں اس نظریے کی تباہ کاریاں بھی دیکھ لیں جبکہ ۱۹۱۴ء میں جنگِ عظیم اول چھڑ گئی اور وہ ۱۹۱۸ء تک جاری رہی جس میں نسلِ انسانی کا اس بڑے پیمانے پر وحشیانہ قتل ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی پہلے اتنی خوں ریزی نہ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں آئندہ جنگ کو روکنے کے لیے ’’لیگ آف نیشنز‘‘ کا بے سود قیام عمل میں لایا گیا۔ اقبال نے My Country Right Or Wrong کے انسانیت انسانیت کش نظریے کا سختی سے نوٹس لیا۔ اس نے یورپ کے رنگ، نسل، وطن اور زبان کے عناصر چہارگانہ پر مبنی معیارِ قومیت کو ٹھکرا دیا۔
اقبال نے تہذیب مغرب کی قباحتوں کو بروقت محسوس کر کے ان کے خلاف اس وقت اظہارِ خیال کر دیا تھا جب سلطنتِ انگلشیہ کے حدود وثغور اس قدر پھیلے ہوئے تھے کہ آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے وسیع علاقے ان کے زیرفرمان تھے اور کہنے والے سچ کہتے تھے کہ حکومتِ برطانیہ کی قلمرو میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اقبال نے ۱۹۰۷ء میں بڑی حوصلہ مندی سے سچی بات کر دی، فرمایا:
دیارِ مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرِ کم عیار ہو گا
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا
ملاحظہ کیجیئے کہ کس حزم و تیقن سے اقبال سطوتِ رفتار دریا کے انجامِ نافرجام کی خبر دے رہے ہیں؎
دیکھ لو گے سطوتِ رفتارِ دریا کا مآل
موجِ مضطر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی
یوں بلا خوفِ تردید کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کے مجدد شرف کا راز اس کے اس عظیم کارنامے میں پوشیدہ ہے کہ اس نے مسلم قوم کی کو ملّی تعرف و توسم دیا، قومی شناخت دی، اسے وہ درد عطا کیا جس میں ان کی دو صدیوں کے مرضِ غلامی سے شفایاب ہونے اور پریشاں نظری سے نجات پانے کا مداوا تھا۔
دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی
دارو کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا
ایک طرف اس قوم کو اس کا تابناک و شاندار ماضی یاد دلایا تو دوسری طرف مغرب کی چکاچوند کو جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری کہہ کر تہذیبِ نو کے منہ پر پورے زور سے تھپڑ رسید کیا۔
نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی
یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے
علمی اور فکری سطح پر مغرب کے ڈھول کا پول کھولا، شخصی زندگی میں مغرب زدہ طبقے اور لندن پلٹ لوگوں کے برعکس درویشانہ انداز رکھا۔ تہذیبِ مغرب کا ذرا برابر اثر قبول نہیں کیا بلکہ ’’بانگِ درا‘‘ سے لے کر ’’ارمغانِ حجاز‘‘ تک ان کا سارا اردو اور فارسی کلام پڑھ جائیے، آپ کو معلوم ہو گا کہ ان کا دل دھڑکتا تھا تو اسلامی غیرت سے، ان کی آنکھ دیکھتی تھی تو دیارِ حجاز کا فردوس نظر نظارہ، اور ذہن سوچتا تھا تو قرآنی نقطۂ نگاہ سے۔ بلاشبہ علومِ شرق و غرب پڑھ لیے مگر بایں ہمہ اسے روح میں درد و کرب اترتا دکھائی دیتا ہے ؎
پڑھ لیے میں نے علومِ شرق و غرب
روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب
آخر اس کا علاج وہ رومی کے جامِ آتشیں اور قرآن کے پیامِ انقلابِ آفریں کے سوا کہیں نہیں پاتا۔ یورپ سے واپسی پر بجائے مغرب زدگی کے اس نے اپنے افکار کے قرآنی ہونے کا دعوٰی کر دیا اور یہ دعوٰی اس بلند آہنگی سے کیا کہ معلوم ہونے لگا کہ عمر بھر اس نے قرآنی فکر کے پرچار کی ٹھان لی ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ۱۹۱۴ء میں اس کا یہ دعوٰی ۱۹۳۷ء تک اس طرح سوزِ دروں میں ڈھل گیا کہ اس کے کلام کا حرف حرف سرزمین طیبہ کے لیے مچلتے ہوئے جذبات اور گداز عطوفتوں کی آماجگاہ بن گیا۔ آخری مجموعۂ کلام کا نام بھی اسی مناسبت سے ’’ارمغانِ حجاز‘‘ رکھا۔ اسرارِ خودی میں اس دعوٰی کا رنگ، ڈھنگ اور آہنگ ملاحظہ فرمائیے اور پھر سوچیئے کہ سوچ کا یہ دھارا آئندہ سالوں میں کن تلاطم خیزیوں اور گرداب انگریزیوں کا مظہر ہے۔
گر دلم آئنۂ بے جوہر است
گر بحرفم غیر قرآں مضمر است
پردۂ ناموس فکرم چاک کن
ایں خیاباں راز خارم پاک کن
تنگ کن رخت حیات اندر برم
اہل ملّت را نگہ دار از شرم
اور آخری شعر میں تو قیامت ہی ڈھا دی ہے ؎
روز محشر خوار و رسوا کن مرا
بے نصیب از بوسۂ پا کن مرا
اواخر عمر میں تو اس کی دردمندی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ ذرا سی ٹھیس پر ابگینے کی طرح پھوٹ بہتا ہے۔ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کلام میں حیات آفرینی کے وہ داعیے بھر دیے ہیں اور جذب و رقّت کے وہ طوفاں اٹھائے ہیں کہ ہر لمحہ وارفتگی و سرگشتگی کے بند ٹوٹ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ذرا اس سیلاب بلاخیز کا انداز دیکھیئے:
شبے پیش خدا بگریستم زار
مسلماناں چرا زارند و خوارند
ندا آمد نمی دانی کہ ایں قوم
دلے دارند و محبوبے ندارند
تصور ہی تصور میں سفرِ حج درپیش ہے، مکہ سے مدینۃ الرسولؐ کو روانگی کے وقت صحرائے عرب کی مسافتوں کو
سحر با ناقه گفتم نرم تر رو
که راکب خسته و بیمار و پیر است
قدم مستانه زد چنداں که گوئی
بپایش ریگ ایں صحرا حریر است
ملخصًا کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کی کثیر الجہات شخصیت کو جس پہلو سے دیکھا جائے وہ ایک ترشا ہوا بوقلموں ہیرا ہے۔ وہ شاعر ہے، وہ سیاست دان ہے، وہ قانون دان ہے، وہ ماہر اقتصادایت ہے، وہ مفکر ہے، وہ مصلح ہے، وہ ایک ایسا عالم ہے جس نے علم و ادب کے سرچشموں سے اپنی تشنہ لبی کا سامان کا ہے۔ اس کے کمالات علمی و اصلاحی کا ہر پہلو امتیازی شان کا حامل ہے مگر اس کا سب سے بڑا سرمایۂ حیات اور وجۂ فضیلت و عظمت یہ ہے کہ اس نے مغرب کی ظاہری چمک چمک کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ مسلمان قوم کو چودہ صدیوں کی دوری کے باوجود قرنِ اوّل کی دل کش اور دل گداز فضاؤں میں لے گیا۔ تہذیبِ جدید اور تمدنِ مغرب کے بودے کن کو ظاہر کیا۔ فلسفۂ خودی کا خوبصورت تصور دے کر اسلامی فکر کی توانائی اور اسلامی تمدن کے عملی مظاہر کا تفوق کھول کر بیان کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بتایا کہ اسلامی فکر میں روح عمل اتر ہی نہیں سکتا جب تک سرکارِ دو جہاںؐ کی ذات والا کو محورِ حیات نہ مان لیا جائے اور اس پیغمبرِ اعظم و آخر سے رابطۂ محبت اس درجہ استوار نہ کر لیا جائے کہ دنیا جہاں کی نعمتیں ہیچ نظر آنے لگیں۔ کیوں نہ ہو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو فرمایا:
لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِن وَّالِدِہٖ وَ وَلَدِہٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ۔ (بخاری و مسلم)
’’تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔‘‘
دوسرے شعراء و مصلحین پر یہی وجۂ امتیاز اقبال کے مجدد شرف کی علت نمائی ہے ؎
بمصطفٰی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است
شہادت کا آنکھوں دیکھا حال
کمانڈر عابد فردوسیؒ، حاجی عمران عدیلؒ، مطیع الرحمانؒ اور رفقاء
عدیل احمد جہادیار
افغانستان کے شہر خوست کے جنوب کی طرف واقع پہاڑی سلسلہ میں طورہ غاڑہ کے قریب ایک غار میں بڑی بڑی پگڑیوں والے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ غار کے باہر ہر دس پندرہ منٹ کے بعد ایک ڈاٹسن یا جیپ آ کر رکتی اور اس میں سے کچھ افراد نکل کر غار کی طرف بڑھتے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر غار کے باہر کھڑے کلاشنکوفوں سے مسلح پہرہ دار ان کو راستہ دے دیتے۔ ڈاٹسنوں اور جیپوں میں آنے والے حضرات خوست جنوبی کے افغان مجاہدین کے کمانڈر تھے اور یہ سب یہاں پر دشمن پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک نیلے رنگ کی ڈبل سیٹر ڈاٹسن اور ایک سرخ پک اپ ڈاٹسن غار کے قریب آ کر رکی۔ ڈبل سیٹر سے لانبے قد کی بڑی سی پگڑی باندھے ایک پر رعب شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ خوبصورت چہرے اور گھنی داڑھی والے بزرگ خوست جنوبی کے ہردلعزیز اور تحصیل درگئی کے فاتح مولانا پیر محمد روحانی صاحب تھے۔ ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ سرخ ڈاٹسن پر حرکت الجہاد الاسلامی کی حربی کونسل کے نائب صدر اور کمانڈر نصر اللہ منصور لنگڑیال صاحب تھے۔
مولانا پیر محمد کی آمد پر شورٰی کی کارروائی شروع ہوئی، یہ شورٰی تحصیل درگئی کی فتح (جو کہ مولانا پیر محمد صاحب کی قیادت میں فتح ہوئی تھی) کے بعد اب خوست شہر پر ایک اجتماعی حملہ کرنے کا پروگرام بنانے کے لیے ہو رہی تھی۔ اس شورٰی میں افغانستان میں جہاد کرنے والی تمام تنظیموں کے سرکردہ افراد شرکت کر رہے تھے۔ اتحادِ اسلامی کی طرف سے مولانا پیر محمد روحانی (امیر عمومی قرارگاہ جنوبی)، حزبِ اسلامی (خالص) کی طرف سے مولانا طور، حزبِ اسلامی (حکمت یار) کی طرف سے انجینئر فیض محمد، دیگر کماندانوں میں بادشاہ گل، کمانڈر ڈاکٹر نصرت اللہ، حرکت الجہاد الاسلامی کی طرف سے کمانڈر نصر اللہ لنگڑیال شرکت کر رہے تھے۔
مختلف مشوروں کے بعد طے پایا کہ ۲۹ ستمبر بروز جمعہ کو حملہ کیا جائے اور پہلے حملہ میں شیخا میر علاقہ داری اور اس کی اردگرد کی پوسٹوں پر حملہ ہو اور ان کی فتح کے بعد اس سے آگے واقع پوسٹوں پر یورش کی جائے۔ اس میں اسلحہ کی تقسیم، توپوں کے نصب کرنے کی جگہ اور اہداف بھی زیرغور آئے اور پھر ان کی تقسیم اور توپ خانہ کے اہداف بھی مقرر کیے گئے۔ حملہ ۲۹ ستمبر کی صبح فجر کے وقت شروع ہونا تھا۔ پہلے دو گھنٹے توپ خانہ نے گولہ باری کرنی تھی پھر ایکشن گروپ نے حملہ کرنا تھا۔ ایکشن گروپ میں ہر کمانڈر چالیس چالیس آدمی دے رہا تھا، یہ سب طے کرنے کے بعد سب اپنے اپنے مراکز کی طرف روانہ ہو گئے۔
۲۸ ستمبر ۱۹۸۹ء نسبتًا گرم دن تھا۔ تحصیل درگئی (جو کہ فتح ہو چکی ہے) کی بستی کے سرے پر واقع اونچے پہاڑوں کی ڈھلوان کی طرف جہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں واقع ہیں وہاں ایک بڑے لاغاٹ (برساتی نالے) کے دائیں ہاتھ ایک پہاڑی کی کھوہ میں دو خیمے لگے ہوئے تھے، یہ خیمے حرکت الجہاد الاسلامی کا عارضی مرکز تھے۔ یہ مرکز یشرا میں اس جگہ پر واقع تھا جہاں سے ایک سڑک نیچے میدان خوست کو جاتی ہے اور ایک علاقہ باڑی کی طرف جاتی ہے۔ ایک خیمے میں مجاہدین جمع تھے اور کماندار نصر اللہ لنگڑیال صاحب جنگ کے لیے مجاہدین کا چناؤ کر رہے تھے۔ چونکہ مولانا پیر محمد اور حرکت کا مرکز ایک ہی ہے اس لیے جنگ کے لیے بیس ساتھی حرکت کے ہونے تھے اور بیس مولانا پیر محمد صاحب کے۔ جناب کماندار صاحب نے مجاہدین سے کہا کہ وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جو جہانداد غنڈ کی پہلی فتح یا دوسری فتح میں شامل رہے ہیں۔ موجود ساتھیوں کی اکثریت ان جنگوں میں حصہ لے چکی تھی اس لیے بہت سے ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔
کماندار صاحب ساتھیوں کا چناؤ کرنے لگے اور مجاہد ظہیر کاشمیری سے کہا کہ وہ ساتھیوں کے نام لکھیں۔ انیس ساتھیوں کے جب نام لکھے جا چکے تو اب ایک ساتھی کا نام رہ گیا۔ کماندار صاحب کشمکش میں تھے کہ کس کا نام لکھیں کہ ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی عمران عدیل کا نام تو آپ نے لکھا نہیں، وہ جہانداد غنڈ کی پہلی فتح میں شریک تھے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے غنڈ کے اندر داخل ہو کر نعرہ فتح مارا تھا اور اذان دی تھی۔ کماندار صاحب نے پوچھا عمران کہاں ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ باہر ہیں۔ کماندار صاحب نے ظہیر کاشمیری سے کہا کہ اس کا نام بھی لکھو۔ تشکیل مکمل ہوئی تو کماندار صاحب نے جنگ کے بارے میں ہدایات دیں اور ان سے کہا کہ گروپ کمانڈر عابد فردوسی صاحب! آپ جنگ کے امیر ہوں گے اور ساتھیوں سے کہا کہ اپنی مکمل تیاری کر لیں کسی وقت بھی روانگی کا آرڈر مل سکتا ہے اور رائفلوں وغیرہ کو صاف کر لیں اور کارتوس وغیرہ بھائی رحمت سے لے لیں۔
اس کے بعد تمام ساتھی اپنی اپنی تیاری کرنے لگے، کئی ساتھی غسل کرنے اور نئے کپڑے پہنے لگ گئے اور بعض ساتھی اپنی رائفلیں صاف کرنے لگے، ہر مجاہد میں جوش اور ولولہ کا ایک نیا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی احسان اللہ کاشمیری غسل کر رہے تھے، راقم نے ان کے پاس جا کر کہا کہ بھائی احسان کیوں شہید یا زخمی ہونے کا سامان کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہی تو آئے ہیں۔ راقم نے یہ جملہ مذاق میں اس لیے کہا تھا کہ اکثر محاذ پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ساتھی اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر جاتے ہیں یعنی غسل کر کے اور سر پر تیل لگا کر پگڑی باندھ کر آنکھوں میں سرمہ ڈال کر اور کپڑوں پر خوشبو لگا کر دلہا بن کر جب جاتے ہیں تو ان شہادت کے متوالوں کی مراد بر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں، شہادت یا زخمی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں بلکہ یہ تو محاذ کا ایک مشاہدہ ہے۔
۲۸ ستمبر عشاء کے وقت مولانا پیر محمد روحانی صاحب تشریف لائے، ان کے ہمراہ تقریباً تیس مجاہدین تھے اور دو گاڑیاں ان کے ہمراہ تھیں۔ تمام ساتھی چلنے کے لیے تیار تھے۔ ایک ڈاٹسن لیے ظہیر کاشمیری بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس گاڑی پر مجاہدین کو باڑی پہنچانا تھا۔ مولانا پیر محمد روحانی صاحب نے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دیں اور چلنے کا حکم فرمایا۔ تمام ساتھی ڈاٹسن پر سوار ہونے لگے۔ ڈاٹسن پر سامان بھی کافی لدا ہوا تھا اس لیے تمام ساتھیوں کا اس میں سمانا مشکل ہو رہا تھا اس لیے بھائی شبیر سے کہا گیا کہ وہ جیپ بھی تیار کریں اور کچھ ساتھیوں کو اس پر لے جائیں۔ جیپ بھی تیار کر لی گئی اور پھر تمام ساتھی ایک دوسرے سے ملنے لگے، اور جانے والے ساتھی اور رہ جانے والے ساتھی ایک دوسرے سے کہا سنا معاف کروانے لگے۔ آخر تمام ساتھی دعا کے بعد مرکز سے روانہ ہوئے۔
رات بے حد سیاہ تھی اور آسمان کہیں کہیں سے ابر آلود تھا۔ دور نیچے میدان میں دشمن کی توپیں اور مشین گنیں چل رہی تھیں۔ دشمن تمام دن اور رات اس خوف سے کہ کہیں مجاہدین اچانک اس پر حملہ نہ کر دیں اپنی پوسٹوں کے اردگرد مسلسل توپیں اور گنیں چلاتا رہتا ہے۔ اب جس جگہ سے مجاہدین نے باڑی کی طرف جانا تھا وہ راستہ تھا تو چھپا ہوا لیکن اگر رات کے اندھیرے میں یہاں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹیں روشن کی جاتیں تو گولہ باری اور بمباری کا شدید خطرہ تھا۔ اس وقت بھی ایک طیارہ نیچے میدان میں جہاں والیم پوسٹ پر (جو کہ فتح ہو چکی ہے) اتحادِ اسلامی اور حرکت کے مجاہدین موجود تھے بمباری کر رہا تھا۔ راستہ بہت خطرناک تھا اس لیے کہ اردگرد دشمن نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں۔ یہ راستہ بھی کماندار نصر اللہ لنگڑیال نے دیگر مجاہدین کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔
خیر رات تین ساڑھے تین بجے کے قریب مجاہدین باڑی پہنچ گئے۔ یہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مجاہدین کے گروپوں کو ملا کر تشکیل کی گئی۔ حملہ علاقہ داری شیخامیر اور اس کے اردگرد کی پوسٹوں پر تھا۔ اسی طرح شہر خوست کے شمال مغرب کی طرف سے بھی دوسرے مجاہدین نے حملہ کرنا تھا۔ مجاہدین آرام کرنے کے بعد دشمن کی طرف چل پڑے۔ رات کا وقت تھا اور ان لوگوں کو اسی اندھیرے میں دشمن کے نزدیک ہونا تھا۔ ان مجاہدین کو سفر کی وجہ سے نیند کا موقع بھی نہیں ملا تھا لیکن یہ اللہ کے سپاہی محمد عربیؐ کے غلام جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے دشمن کے بالکل نزدیک پہنچ کر مورچے سنبھالنے تھے اور اس کے بعد پھر مجاہدین کے توپ خانے نے دشمن پر گولہ باری کرنی تھی اور اس طرح اس توپ خانے نے مجاہدین کی پیش قدمی کے ساتھ اردگرد کی دوسری پوسٹوں کو مصروف کرنا تھا۔
ان مجاہدین نے نمازِ فجر راستہ میں ادا کی اور پھر دشمن سے نزدیک ہونے لگے حتٰی کہ دشمن سے دو اڑھائی سو میٹر کے فاصلہ پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر یہ لوگ رک گئے کیونکہ ریکی گروپ (ترصد گروپ) کے مطابق آگے بارودی سرنگیں تھیں، ان کے یہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد مجاہدین کے توپ خانے سے اکا دکا میزائل اور توپ کے گولے فائر ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ جب میزائل اور گولے ہدف پر لگنے لگے تو پھر ایک دم اکٹھے بارہ بارہ میزائل چھوڑے جانے لگے۔ اسی طرح توپوں کے گولے بھی چلنے لگے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے فائر ہونے کے بعد دشمن کی طرف سے بھی ٹینک کے گولے اور BM13 میزائل فائر ہونے لگے۔ اسی طرح شہر خوست کے شمال مغرب میں بھی یہی حال تھا۔ ادھر گولے چل رہے تھے میزائل پھٹ رہے تھے اور یہاں ایکشن گروپ کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور کئی ساتھی ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ کسی ساتھی مجاہد کے چہرے سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوفزدہ یا پریشان ہے۔
اسی اثنا میں اس ایکشن گروپ کے عمومی کمانڈر نے ایک مجاہد کو بارودی رسی ڈالنے کو کہا۔ مجاہدین اس وقت ایک لاغاٹ (برساتی نالہ) میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجاہد اپنے دو تین دیگر ساتھیوں کے ساتھ بارودی رسی، جو کہ مائن فیلڈ (بارودی سرنگ) کو ناکارہ کرتی ہے، لے کر اس برساتی نالے کے سرے پر چڑھا تو ایک زور دار دھماکہ ہوا، اس مجاہد کا پاؤں مائن پر آ گیا تھا اور وہ دھماکہ مائن پھٹنے کا تھا۔ مائن پر پاؤں آنے کی وجہ سے اس مجاہد کا پنڈلی کے قریب سے پاؤں کٹ گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی کو فورًا نیچے لاغاٹ میں لایا گیا اور مرہم پٹی کی گئی۔ اس وقت اس کو پیچھے منتقل کرنا مشکل تھا اس لیے اس کو یہیں پر لٹا دیا گیا۔ مجاہدین اور دشمن کی طرف سے گولہ باری ایک دوسرے پر شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ خوست کے اس علاقے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ سی لگ گئی ہو۔
دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک میزائل مزاحمتی گروپ والے مجاہدین کے درمیان گرا اور پھر دھوئیں اور مٹی کا ایک بادل سا چھا گیا۔ جب یہ دھواں اور مٹی کچھ کم ہوئے تو ایک لرزہ خیز منظر سامنے تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو مجاہدین ٹھیک ٹھاک تھے ان میں سے کئی اب خاک و خون میں لت پت تھے۔ ابھی مجاہدین سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ یکے بعد دیگرے دو میزائل اور مجاہدین کے درمیان میں آ کر لگے، پھر تو ہر طرف ایک کہرام سا مچ گیا۔ ہر طرف زخمی اور شہید پڑے تھے۔ پہلے ہی میزائل سے حرکت کے دو مجاہد گروپ کمانڈر عابد فردوسی اور بھائی عمران عدیل شہید ہو گئے۔ دوسرے میزائل سے بھائی مطیع الرحمٰن بھی شہید ہو گئے۔ لاغاٹ میں ہر طرف خون ہی خون تھا، وہ نالہ جو کبھی پانی سے بہتا تھا اب بلامبالغہ شہیدوں اور زخمیوں کے لہو سے بہہ رہا تھا۔ میزائل لگنے سے پینتیس کے قریب مجاہدین شہید اور پچاس کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔
اب دشمن پر حملہ تو کیا نہیں جا سکتا تھا اس لیے جو ساتھی بچ گئے تھے انہوں نے زخمیوں اور شہیدوں کو پیچھے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ان شہیدوں اور زخمیوں کو منتقل کرنا بھی کوئی آسان بات نہ تھی جیسے ہی مجاہدین زخمیوں اور شہیدوں کو نکالنے لگے دشمن کی پوسٹوں کے برجوں پر نصب مشین گنیں گرجنا شروع ہو گئیں اور پھر طیارے بھی بمباری کے لیے پہنچ گئے لیکن اس سب کے باوجود مجاہدین نے ہمت نہ ہاری اور ایک ایک کر کے تمام شہیدوں اور زخمیوں کو پیچھے منتقل کر لیا گیا۔ حرکت کے تین مجاہدین زخمی ہوئے تھے جن میں احسان اللہ کشمیری اور بھائی نیاز (متعلم مدرسہ امدادیہ فیصل آباد) کو کافی شدید زخم آئے تھے۔ ان کو باڑی ہی کے راستے میرانشاہ بھیج دیا گیا اور شہداء کو گاڑیوں میں لاد کر مرکز یشرا لایا گیا۔
ہر ساتھی غمگین تھا اور زبانِ حال سے کہہ رہا تھا کہ کاش یہ ساتھی شہید نہ ہوتے بلکہ میں ان کی جگہ شہید ہو جاتا۔ شہداء میں
- بھائی عابد فردوسی حرکت الجہاد الاسلامی کے بہت ہی فعال ترین اور پرانے مجاہد تھے۔ وہ ۱۹۸۶ء میں محاذ پر تشریف لائے اور شہادت تک اکثر وقت محاذ پر رہے۔ جنوری ۱۹۸۹ء میں ایک معرکہ میں زخمی بھی ہوئے تھے، کئی مہینے جلال آباد میں حرکت کے ساتھیوں کی کمان بھی کی، قرآن کے حافظ تھے اور بہت اچھی قراءت کرتے تھے۔
- اسی طرح بھائی حاجی عمران عدیل اچھڑیاں ضلع مانسہرہ کے رہنے والے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب کے نواسے اور مدیر الشریعہ مولانا زاہد الراشدی کے بھانجے تھے، تقریبًا ایک سال سے حرکت الجہاد الاسلامی کے جیالے مجاہدین کے ساتھ شاملِ پیکار تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلد ترقی حاصل کر لیتے ہیں۔ بھائی عمران عدیل بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ فروری میں جہانداد کی پہلی فتح کی شدید لڑائی میں شریک تھے اور جہانداد پوسٹ میں سب سے پہلے داخل ہو کر انہوں نے نعرۂ فتح بلند کیا تھا اور اذان دی تھی۔
- تیسرے بھائی مطیع الرحمٰن تھے، ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا اور انہوں نے اسی سال المرکز الخالد زبیر شہید سے جنگی تربیت لی تھی۔ شہید مطیع الرحمٰن کو ان کی وصیت کے مطابق مولانا عبد الرحمٰن شہید کی قبر مبارک کے قریب وہیں یشرا میں دفنا دیا گیا۔
بھائی عمران عدیل شہید اور بھائی عابد فردوسی شہید کو ان کے گھروں میں پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ شہید عابد فردوسی کے ساتھ راقم نے ان کے گھر فیصل آباد جانا تھا اور بھائی شہید عمران عدیل کے ساتھ بھائی سید احمد صاحب نے جانا تھا۔ میرانشاہ سے ہم اکٹھے بنوں تک گئے۔
جب یہ حضرات جنگ کے لیے جا رہے تھے تو بھائی عمران عدیل مجھ سے ایک عجیب طرح سے ملے اور فرمایا عدیل بھائی! کہا سنا معاف کر دینا۔ حالانکہ اور ساتھی بھی مجھے جاتے ہوئے ملے اور انہوں نے بھی تقریباً یہی الفاظ کہے تھے لیکن جب بھائی عمران نے یہ الفاظ کہے تو نجانے کیوں میرے دل نے کہا کہ یہ ضرور شہید ہوں گے۔ اور جنگ والے دن میں اکثر ان کی سلامتی کی اور زندگی کی دعا مانگتا رہا لیکن ہوتا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔
بنوں پہنچ کر میں نے عمران شہید والی گاڑی رکوائی کیونکہ اب ہمارے راستے جدا جدا تھے، میں نے تابوت کھولا تو ایک نہایت ہی اچھی خوشبو محسوس کی۔ میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پیشانی پر سے ان کے بال ہٹائے تو مجھے ان کی پیشانی، باوجود ان کے ۱۲ گھنٹے پہلے شہید ہونے کے، گرم محسوس ہوئی۔ اللہ اللہ، جب ان کو اٹھا کر یشرا مرکز میں ہم لائے تھے تو بھی اس وقت ان سے اور دوسرے دونوں شہداء سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اور گرم ماتھا یہ کہہ رہے تھے کہ ؎
بنا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقاں پاک طینت را
آپ نے پوچھا
ادارہ
اشتراکیت کا فلسفہ کیا ہے؟
سوال: اشتراک کا فلسفہ کیا ہے اور یہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ (محمد غفران، اسلام آباد)۔
جواب: اشتراک کا فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں انسانوں کے درمیان زیادہ تر جھگڑے زمین، مال اور عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لیے یہ تینوں چیزیں کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہو سکتیں بلکہ یہ تینوں تمام انسانوں کے درمیان کسی تعیین کے بغیر مشترک ملکیت ہیں۔ یہ فلسفہ سب سے پہلے پارسیوں (مجوسیوں) کے ایک راہنما مزدک نے پیش کیا اور کہا کہ ایک شخص جو کچھ کماتا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ سب لوگوں کی مشترک ہے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مرد ہر عورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
ظہورِ اسلام کے بعد اسی فلسفہ کو عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں بابک خرمی نے دوبارہ پیش کیا اور زن، زر اور زمین کو مشترک ملکیت قرار دے کر اس کا پرچار شروع کر دیا لیکن خلیفہ معتصم باللہ نے اسے قتل کرا دیا۔ موجودہ دور میں انفرادی ملکیت کی نفی کا یہ فلسفہ منظم شکل میں سب سے پہلے کارل مارکس نے پیش کیا اور اسے ’’کمیونزم‘‘ کا نام دیا۔ روس، چین اور مشرقی یورپ کے اشتراکی انقلاب اسی فلسفہ پر برپا ہوئے لیکن کہیں بھی کارل مارکس کا فلسفہ اصلی شکل میں نافذ نہ کیا جا سکا بلکہ ’’سوشلزم‘‘ کے نام سے اس کے قریب قریب ایک جبری نظام ان ممالک پر مسلط کر دیا گیا مگر وہ بھی اب دم توڑ رہا ہے۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ اور معراجِ جسمانی
سوال: بعض حضرات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کی قائل نہ تھیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ (عبد الغفور، اوکاڑہ)
جواب: یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان ہے کیونکہ خود حضرت عائشہؓ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہٰی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ میں اس امر پر اختلاف تھا کہ معراج کے اس سفر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بلاحجاب زیارت کی ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہؓ اس کی قائل نہیں تھیں اور ان کا ارشاد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہٰی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل میں زیارت ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۸ میں یہ روایت منقول ہے۔
باقی رہی بات معراج جسمانی کی تو جب حضرت عائشہؓ سدرۃ المنتہٰی تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے، جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کی بے حجاب زیارت نہ ہونے کا موقف پیش کر رہی تھیں تو ان کی طرف معراج جسمانی کے انکار کی نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے؟
ربوہ کا معنٰی کیا ہے؟
سوال: بعض علماء کی طرف سے ربوہ کے نام کی تبدیلی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ربوہ کا معنٰی کیا ہے اور اس مطالبہ کا پسِ منظر کیا ہے؟ (عبد السلام، فیصل آباد)
جواب: ربوہ عربی زبان میں اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں اور قرآن کریم میں حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کے حوالہ سے ’’ربوہ‘‘ کا لفظ مذکور ہے کہ ’’وَاٰوَیْنَاھُمَآ اِلٰی رَبْوَۃٍ‘‘ ہم نے ان دونوں کو اونچے ٹیلے پر جگہ دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا چونکہ دعوٰی یہ ہے کہ وہ خود عیسٰی بن مریم ہے اور احادیث رسولؐ میں مسیحؑ اور عیسٰیؑ کی دوبارہ تشریف آوری کی جو بشارت دی گئی ہے وہ اس کے بارے میں ہے، اس لیے قیامِ پاکستان کے بعد قادیانیوں نے ایک سازش کے تحت اپنے نئے ہیڈکوارٹر کا نام ’’ربوہ‘‘ رکھ دیا تاکہ ناواقف لوگ جب قادیانیوں کے ہیڈکوارٹر ربوہ کا نام قرآن کریم میں دیکھیں گے اور حضرت عیسٰی علیہ السلام کے حوالہ سے ربوہ کا تذکرہ ہو گا تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں دھوکہ کا شکار ہو جائیں گے۔
چنانچہ عملًا ایسا ہو بھی رہا ہے۔ افریقی ممالک میں جہاں قادیانیوں کی سرگرمیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، جب علماء اسلام وہاں جا کر قادیانیت کی تردید کرتے ہیں تو بہت سے سادہ لوح لوگ ان سے جھگڑتے ہیں کہ ’’ربوہ‘‘ کا ذکر تو خود قرآن کریم میں ہے، تم اس کی تردید کیوں کرتے ہو؟ اسی وجہ سے علماء اسلام حکومتِ پاکستان پر اس بات کے لیے زور دیتے ہیں کہ ربوہ کا نام سرکاری طور پر تبدیل کر دیا جائے کیونکہ یہ نام بیرون ملک بہت زیادہ لوگوں کی گمراہی کا باعث بن رہا ہے۔
قیامِ پاکستان اور جمعیۃ علماء اسلام
سوال: عام طور پر مشہور ہے کہ علماء دیوبند نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ کہاں تک درست ہے؟ (عبد الکبیر، مانسہرہ)
جواب: یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ آل انڈیا جمعیۃ علماء اسلام نے باقاعدہ جماعتی حیثیت سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ اس جمعیۃ کا قیام ۱۹۴۵ء میں عمل میں لایا گیا تھا اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کو اس کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان کی قیادت میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے تحریک پاکستان میں سرگرم کردار ادا کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تحریکِ پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے موقع پر صوبہ سرحد کا تفصیلی دورہ کر کے رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا۔ جبکہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ نے سلہٹ کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں کے عوام کو مسلم لیگ اور پاکستان کی حمایت کے لیے آمادہ کیا۔
یہی وجہ ہے کہ قیامِ پاکستان کے بعد مسلم لیگی زعماء نے کراچی میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اور ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ کے ہاتھوں سب سے پہلے پاکستان کے قومی پرچم کے لہرانے کا اہتمام کیا جو تحریکِ پاکستان میں ان کی خدمات اور جدوجہد کا اعتراف تھا۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’تحریف کے یہ مجرم‘‘
تالیف: حافظ محمد اقبال رنگونی
صفحات: ۱۵۲ ۔کتابت و طباعت معیاری
ناشر:ادارہ الہلال اسلامک اکیڈمی، مانچسٹر، برطانیہ
قرآن کریم سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں توراۃ، زبور اور انجیل میں ان کے پیروکاروں نے لفظی اور معنوی تحریف کر کے انہیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہنے دیا اور آج بائیبل کے نام سے ان کتابوں کا جو مجموعہ مختلف زبانوں میں شائع کیا جاتا ہے اس کا بیشتر حصہ ان تحریفات، ترامیم اور اضافہ جات پر مشتمل ہے جو مختلف ادوار میں عیسائی علماء نے وقتی مصلحتوں اور اغراض کے تحت ان مقدس کتابوں میں شامل کر دیے ہیں۔
یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی کے بس کی بات نہیں اور تاریخی حقائق اس حقیقت کا مکمل طور پر ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض عیسائی علماء موجودہ بائیبل کو وحی الٰہی ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور مغالطہ آفرینی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے عقیدت مندوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ علماء اسلام نے ہر دور میں عیسائی دانشوروں کی اس فریب کاری کا پردہ چاک کیا ہے اور اس موضوع پر متعدد قابلِ قدر تصانیف موجود ہیں۔
زیرنظر کتابچہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی کی تصنیف ہے۔ حافظ صاحب موصوف اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کے ماہنامہ ’’الہلال‘‘ کے مدیر ہیں، انہوں نے ’’الہلال‘‘ میں بائیبل کے محرف ہونے پر ایک مضمون لکھا جس کے جواب میں اولڈھم برطانیہ کے پادری سٹیون مسعود صاحب نے ایک رسالہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ موجودہ بائیبل اصلی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ رنگونی صاحب نے زیرنظر کتابچہ میں پادری صاحب موصوف کے دلائل کا تجزیہ کیا ہے اور ان کے مغالطوں کے تاروپود بکھیرتے ہوئے ناقابلِ تردید دلائل کے ساتھ ایک بار پھر یہ بات واضح کر دی ہے کہ موجودہ بائیبل اصلی نہیں ہے اور نہ ہی تورات، انجیل اور زبور میں سے کوئی آسمانی کتاب اس وقت اصلی حالت میں دنیا میں موجود ہے۔
’’ہدایہ علماء کی عدالت میں‘‘ (حصہ اول)
مصنف: مولانا حبیب اللہ ڈیروی
ناشر: مکتبہ عزیزیہ، دال بازار، منڈی لوہاراں، گوجرانوالہ
صفحات: ۲۵۶ ۔کتابت و طباعت معیاری۔ قیمت ۳۶ روپے
ہدایہ فقہ حنفی کی مستند اور معروف کتاب ہے جس میں فقہ حنفی کے مسائل کو نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے اس میں استدلال و استنباط کا ایسا منفرد اسلوب اختیار کیا ہے جس نے ہدایہ کو دنیائے اسلام میں قانونِ اسلامی کے ایک اہم ماخذ کی حیثیت دے دی ہے۔ اور نہ صرف علماء اسلام بلکہ غیر مسلم ماہرینِ قانون بھی اسلامی قوانین کی تعلیم و تشریح کے لیے ہدایہ سے استفادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مگر ہمارے بعض دوست جن کا ذہن صاحبِ ہدایہ کے استدلال کی گہرائی اور لطافت تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا وقتًا فوقتًا ہدایہ کے مختلف مسائل پر اعتراض اور اس کے معائب و نقائص کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں۔
اس سلسلہ میں حال ہی میں گوجرانوالہ کے ایک دوست نے ’’ہدایہ عوام کی عدالت میں‘‘ کے نام سے ہدایہ پر اپنے اعتراضات کا مجموعہ شائع کیا ہے جس کا جواب مولانا حبیب اللہ ڈیروی نے زیرنظر کتابچہ کی صورت میں دیا ہے اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ہدایہ پر کیے جانے والے اکثر اعتراضات کم فہمی یا عناد پر مبنی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
’’کمیونزم کا فتنہ‘‘
از: مولانا محمد اسحاق صدیقی
ناشر: صدیقی ٹرسٹ، نسیم پلازا، نشتر روڈ، کراچی
صفحات: ۳۶ قیمت: ایک روپیہ
’کمیونزم‘‘ ایک جدید سیاسی اور معاشی نظام کا نام ہے جو یورپ کے سرمایہ دارانہ و جاگیردارانہ نظام کے مظالم کے ردعمل کے طور پر ابھرا اور طبقاتی کشمکش کے حوالہ سے کمزور طبقات و اقوام کو لپیٹ میں لیتے ہوئے مختلف ممالک میں انقلاب کا عنوان بن گیا۔ لیکن اس کی بنیاد چونکہ خدا کے انکار اور اجتماعی جبر کے غیرفطری فلسفہ پر تھی اس لیے زیادہ دیر نہیں چل سکا اور اب بتدریج فکری اور سیاسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔
زیر نظر رسالہ میں مولانا محمد اسحاق صدیقی نے کمیونزم کے غیر فطری فلسفہ کا پس منظر واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نقائص کی نشاندہی کی ہے اور اسلام کے ساتھ اس کے فرق و اختلاف کے اظہار کے علاوہ کمیونسٹ تحریک کے مقاصد اور طریقِ کار پر بھی روشنی ڈالی ہے۔
’’اصلی شادی کارڈ‘‘
مرتب: خواجہ محمد اسلام
ملنے کا پتہ: تبلیغی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور
صفحات: ۷۲ ۔ کتابت و طباعت عمدہ
خواجہ محمد اسلام بھلے بزرگ ہیں جو دینی عنوانات پر اصلاحی و تبلیغی کتب و رسائل کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں اور انہیں مختلف حلقوں تک پہنچانے کے لیے پبلسٹی کے بھرپور ذرائع استعمال میں لاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف زبانوں میں ’’موت کا منظر‘‘ شائع کی اور اس کی اس انداز میں تشہیر کی کہ اس کا شمار دنیا کی کثیر الاشاعت کتابوں میں ہوتا ہے بلکہ خود خواجہ صاحب موصوف کے لیے بھی یہ کتاب تعارف کا حوالہ بن گئی ہے۔
زیرنظر رسالہ میں خواجہ صاحب مسلم معاشرہ کی خواتین سے مخاطب ہوئے ہیں اور انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک مسلمان عورت کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی زندگی کس انداز سے بسر ہونی چاہیے۔ ’’اصلی شادی کارڈ‘‘ کا ایک ایڈیشن انتہائی خوبصورت سنہری ٹائٹل کے ساتھ بھی شائع کیا گیا ہے جس کے بارے میں خواجہ صاحب کی خواہش یہ ہے کہ لوگ شادی کے موقع پر مروّجہ رنگین اور مزین شادی کارڈوں کی بجائے اس کتابچہ کے ٹائٹل پر پروگرام چھپوا کر عزیزوں کو بھجوائیں تاکہ خوبصورت شادی کارڈ کا شوق بھی پورا ہو جائے اور اصلاح و دعوت کا ثواب بھی حاصل ہو۔ بہرحال یہ ایک اچھا جذبہ و کوشش ہے جس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیئے۔
زکٰوۃ کا فلسفہ اور حقیقت
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
عبادت کا ایک طریقہ زکٰوۃ ہے۔ زکٰوۃ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کی خوشنودی کی خاطر مال و دولت خرچ کرنے کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہو جائے۔ اس طرح معبود کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا اور ذبیحہ کی قربانی دینا بھی زکٰوۃ کے ملحقات میں سے ہیں۔ جب آدمی کو کوئی تکلیف ومصیبت پیش آتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے اپنے معبودِ حقیقی کی طرف گھبرا کر رجوع کرتا ہے تو پہلے بارگاہِ اقدس میں صدقہ یا اعتاق یا قربانی پیش کرتا ہے۔
زکٰوۃ کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ اموال میں حق معلوم اور حصہ مقرر ہو، یا شرع اس کی تحدید و تعیین کرے۔انسان کے اموال و املاک میں بنیادی چیزیں یہ ہیں:
- نقدین (سونا چاندی)
- مویشی
- اشیاء تجارت، اور
- زراعت اور کھیتی باڑی
ان اموال میں نصاب کا تعین بھی ضروری ہے جس کی مقدار اتنی قلیل بھی نہ ہو جس کے نکالنے میں تکلیف و حرج ہو، اور نہ اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کے پاس اس مقدار کے نصاب کا اکٹھا ہو جانا بہت نادر ہو۔ اسی طرح میعاد کا بھی خیال رکھنا چاہیئے، اس میں بھی اوسط میعاد ملحوظ رکھنی ہو گی۔ یہ سب کچھ اس لیے ضروری ہے کہ صاحبِ مال سے زکٰوۃ لینے کا کام آسان ہو جائے اور اس کے فوائد زیادہ سے زیادہ رہیں۔
(البدور البازغۃ مترجم ص ۳۰۸)
امام ولی اللہ کا پروگرام اور روسی انقلاب
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
لوگ بالعموم یہ جانتے ہیں کہ روسی انقلاب فقط ایک اقتصادی انقلاب ہے، ادیان اور حیاتِ اخروی سے بحث نہیں کرتا۔ ہم ان روسیوں کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کے خیالات و افکار ہم نے معلوم کیے ہیں اور ہم بتدریج اور آہستہ آہستہ نرمی اور لطافت سے امام ولی اللہؒ کا پروگرام، جو انہوں نے حجۃ اللہ البالغۃ میں پیش کیا، ان روسیوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے اسے نہایت ہی مستحسن خیال کیا اور ہم سے پوچھنے لگے کہ کیا کوئی ایسی جماعت اس وقت ہے جو اس پروگرام پر عمل کرتی ہو؟ جب ہم نے نفی میں جواب دیا تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور کہنے لگے کہ اگر کوئی جماعت اس پروگرام پر عمل کرنے والی ہوتی تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور ہم بھی ان میں داخل ہو کر ان کا مذہب اختیار کر لیتے، اور یہ بات ہمارے لیے آسان بنا دیتی ہماری ان مشکلات کو جنہوں نے ہمارے پروگرام کو کسانوں میں نافذ کرنے سے روک رکھا ہے۔
یہ ان روسیوں کی بات کا بلا کم و کاست اور بغیر تحریف کے خلاصہ ہے۔ اس کے بعد یقین ہوا کہ یہ لوگ ہمارے قرآنی پروگرام کو قبول کرنے کی طرف مجبور ہوں گے اگرچہ ایک زمانہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ہم آج کے دور میں عالمی تحریکوں میں سے کسی تحریک کو ایسا نہیں پاتے کہ وہ قرآنی تعلیمات کے خلاف اور مناقض ہو جس طرح انقلابی روس کی تحریک قرآنی پروگرام کے مناقض اور مخالف ہے۔ اور باوجود اس کے وہ بھی مجبور اور مضطر ہیں کہ قرآن اور اس کے پروگرام کی طرف رجوع کریں، باقی تحریکات کا کیا پوچھنا! اور اس چیز نے میرے ایمان میں زیادتی اور قوت پیدا کر دی کہ ہدایت و فلاح قرآن کے نزول کے بعد قرآن کے اتباع پر ہی موقوف ہے۔
(الہام الرحمٰن ص ۷۰)
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کی تعمیر کا آغاز
ادارہ
بحمد اللہ تعالیٰ جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ گوجرانوالہ کے زیراہتمام شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے پہلے تعمیری بلاک کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے لیے جی ٹی روڈ پر لاہور کی جانب اٹاوہ کے ساتھ بتیس ایکڑ زمین خریدی گئی ہے اور تعلیمی کمیٹی کی طرف سے دیے گئے پروگرام کے مطابق آرکیٹیکٹس کی مشہور فرم ندیم ایسوسی ایٹس نے ماسٹر پلان تیار کر لیا ہے جس کی منظوری جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ کی مجلسِ شورٰی کے اجلاس میں دے دی گئی ہے جو گزشتہ دنوں نائب صدر جناب بابو شمیم احمد کی رہائش گاہ پر الحاج محمد رفیق کی زیرصدارت منعقد ہوا۔ اس ماسٹر پلان کے مطابق سردست پہلے دو منزلہ تعلیمی بلاک کی تعمیر شروع کی گئی ہے جس کی ایک منزل میں آٹھ کلاس روم، اساتذہ کے آٹھ کمرے اور دیگر ضروریات شامل ہیں۔ پہلے مرحلہ میں بلاک کی ایک منزل کی تعمیر ایک سال کے اندر کم و بیش تیس لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کی جائے گی اور آئندہ تعلیمی سال سے کالج کی سطح پر تعلیمی کلاسوں کا آغاز کر دیا جائے گا، ان شاء اللہ العزیز۔
ڈسٹرکٹ کونسل گوجرانوالہ نے اٹاوہ ریلوے پھاٹک سے شاہ ولی اللہ یونیورسٹی تک پختہ سڑک کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے اور اس کا سروے کا کام کام شروع ہو چکا ہے جس کے لیے یونیورسٹی کی مجلس انتظامیہ کے سرپرست مولانا زاہد الراشدی اور حافظ بشیر احمد، صدر الحاج میاں محمد رفیق، اور سیکرٹری جنرل شیخ محمد اشرف نے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین جناب رانا نذیر احمد ایم این اے اور دیگر متعلقہ حضرات کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تعلیمی کمیٹی کی سفارش کے مطابق سب سے پہلے تعلیمی شعبہ میں کالج کی کلاسیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ تعلیمی سال سے ایف اے کی کلاسیں شروع کی جائیں گی اور پہلے سال کے لیے میٹرک یا اس کے مساوی وفاق المدارس العربیہ کا سرٹیفکیٹ رکھنے والے طلبہ کو داخلہ مل سکے گا۔ تعلیمی کمیٹی نے درسِ نظامی کے فضلاء کے لیے:
- مقابلہ کے امتحان کی تیاری کے لیے پانچ سالہ کورس
- تفسیر، حدیث، تاریخ، قضاء اور افتاء میں تخصص کی کلاسیں
- انگریزی، عربی، تاریخ، پبلک ڈیلنگ اور دیگر ضروری امور کے دو سالہ کورس
- مختلف مضامین میں ایم اے کے امتحانات کی تیاری، اور
- وکلاء، ججز، تاجروں اور دیگر طبقات کے لیے خصوصی کورسز کا جامع پروگرام مرتب کیا ہے جس پر ان شاء اللہ تعالٰی بتدریج عمل ہو گا۔
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے سربراہ جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ کے سرپرست اعلٰی شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدظلہ العالی نے یونیورسٹی کے تعمیری کام کے آغاز پر اللہ تعالٰی کا شکر ادا کرتے ہوئے جمعیۃ اہل السنۃ کے عہدہ داروں اور ارکان کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ بالآخر مخلص دوستوں کی تمنائیں، کوششیں اور دعائیں رنگ لائی ہیں اور عملی کام کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں کسی بھی سطح پر تعاون کرنے والے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ تمام دوست اور ساتھی پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنی کوششیں تیز کر دیں گے۔
مارچ ۱۹۹۰ء
اسلامی بیداری کی لہر اور مسلم ممالک
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
روزنامہ جنگ لاہور نے ۲۰ فروری ۱۹۹۰ء کی اشاعت میں ہانگ کانگ کی ڈیٹ لائن سے ’’ایشیا ویک‘‘ کی ایک رپورٹ کا خلاصہ خبر کے طور پر شائع کیا ہے جس میں مغربی ممالک میں مسلمانوں کی آبادی اور ان کے مذہبی رجحانات میں روز افزوں اضافہ کو ’’مغرب میں اسلام کی خوفناک پیش قدمی‘‘ کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے چند اہم نکات درج ذیل ہیں:
- صدیوں قبل اسلام مغرب میں صلیبی جنگوں کے حوالے سے داخل ہوا تھا اور پھر نکل بھی گیا تھا لیکن اب اسلام مغرب میں عقیدہ کی تبدیلی، نقل مکانی اور شرح پیدائش میں اضافہ کے حوالہ سے پیش قدمی کر رہا ہے۔
- یورپ اور مغرب میں کمیونزم کا ہوّا ختم ہونے کے بعد اب اسلام کا ہوّا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور نہ صرف مغربی یورپ کے ممالک میں مسلمان اپنا تشخص دریافت کر رہے ہیں بلکہ یوگوسلاویہ، بلغاریہ اور سوویت یونین میں بھی ایسا ہو رہا ہے جہاں مسلمان اور غیر مسلمانوں کے درمیان خونی تصادم کے واقعات روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں۔
- گزشتہ دو دہائیوں میں امریکی مسلمانوں کی تعداد میں دو گنا اضافہ ہوا، مقامی مسلمانوں کی تعداد میں ۱۹۸۰ء کے بعد سے ۲۴ فیصد اضافہ ہوا اور آئندہ ۳۰ برس سے بھی پہلے مسلمانوں کی آبادی یہودیوں سے بڑھ جائے گی اور اس طرح مسلمان امریکہ میں دوسرے نمبر پر آجائیں گے۔ ڈیربورن کے شہر میں مسلمان آبادی کا دس فیصد حصہ ہیں جہاں سرکاری اسکولوں میں مسلمانوں کے تہواروں پر چھٹی کی جاتی ہے اور ہوٹلوں میں سور کا گوشت پیش نہیں کیا جاتا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں مسلمان طلبہ نے رمضان کے دوران کھانے کے الگ اوقات کا مطالبہ منوا لیا ہے۔
یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے اس دینی بیداری کی جو مغربی ممالک میں مقیم مسلمانوں کے دل و دماغ میں کروٹ لے رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کے ستائے ہوئے معاشروں میں اسلامی بیداری کی یہ لہر جہاں اسلام کی صداقت کی دلیل ہے وہاں عالمی معاشرے میں اسلام کے درخشاں مستقبل کی نوید بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور نام نہاد مسلم حکومتیں بھی قائم ہیں، اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی اس عالمی لہر میں خود ان کا رخ کس جانب ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملا اعلی میں ’’وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم‘‘ کے اٹل قانون پر عمل کا فیصلہ ہو چکا ہو اور ہم اپنے گروہی، طبقاتی، شخصی، نسلی اور علاقائی تشخصات و تعصبات کی بھول بھلیوں میں اندلس کی تاریخ دہرانے کے کردار پر ہی قناعت کر بیٹھیں۔
شاید کہ اتر جائے کسی دل میں مری بات
احادیثِ رسول اللہؐ کی حفاظت و تدوین
صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کی خدمات
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
بدقسمتی سے آج ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو خود کو مسلمان کہلاتا ہے اور بایں ہمہ احادیث کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا اور ان سے گلوخلاصی کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ احادیث ظنی ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہ قرآن کریم سے متصادم ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہیں، کبھی کہتا ہے کہ احادیث دوسری تیسری صدی کی پیداوار ہیں، کبھی کہتا ہے کہ یہ عجمیوں کی سازش ہے، اور کبھی جعلی اور موضوع احادیث کو چن چن کر بلاوجہ درمیان میں لا کر ان کی وجہ سے صحیح احادیث پر برستا ہے، کبھی ان کے معانی میں کیڑے نکالتا ہے۔ الغرض مشہور ہے کہ ’’خوئے بدرا بہانہ ہائے بسیار‘‘۔
حافظ ابن تیمیہؒ نے بجا فرمایا کہ ہر زندیق اور منافق کا اس علم کو باطل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے، یہ عمدہ ہتھیار ہے کہ وہ کبھی تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے ایسا فرمایا ہے؟ اور کبھی کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ اور جب ان کے قول اور اس کے معنی کے علم ہی کی پیغمبر سے نفی ہو گئی اور علم ان کی طرف سے حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد احادیث (حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے معارضہ سے مامون ہو کر زندیق اور منافق جو چاہتا ہے اپنی طرف سے کہتا ہے، کیونکہ اسلام کی سرحدیں ان دو تیروں سے محفوظ ہیں ( ایک الفاظِ حدیث اور دوسرا ان کے معانی)۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اگرچہ زبانی کلامی زندیق اور منافق حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و کمال کا اقرار بھی کرتا ہے (محصلہ نقص المنطق ص ۷۵ طبع القاہرہ) ۔ اور کبھی کہتا ہے کہ اگر احادیث حجت ہیں تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ نے وہ کیوں نہیں لکھیں اور لکھوائیں؟ اور کبھی کہتا ہے کہ آپؐ نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث کو مٹانے کا حکم کیوں دیا تھا؟
یہاں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ اہلِ عرب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے قوی حافظے دیے تھے اور وہ کتابت سے زیادہ حفظ پر بھروسہ کرتے تھے اور کتابت کو چنداں وقعت نہ دیتے تھے اور نری کتابت پر اعتماد کو وہ ایک کم درجے کی حیثیت دیتے تھے۔ چنانچہ امام ابو عمر یوسفؒ بن عبد البر المالکیؒ (المتوفی ۴۶۳ھ) اس سلسلہ میں چند قیمتی باتیں نقل کرتے ہیں جو اہل عرب اور اربابِ ذوق کے لیے فائدہ سے خالی نہیں۔
(۱) قال اعرابی حرف فی تامورک خیر من عشرۃ فی کتبک (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۹)
’’بدو کہتا ہے کہ ایک حرف جو تیرے دل میں محفوظ ہے ان دس باتوں سے بہتر ہے جو تیری کتابوں میں درج ہے۔‘‘
اندازہ لگائیں کہ عرب کا بدو کتابوں کا طومار دیکھ کر کس طرح مذاق اڑاتا تھا اور یہ فقرہ بدوؤں میں عام چلتا ہوا فقرہ تھا اور یہ محض اس لیے تھا کہ وہ دولتِ حفظ سے نوازے گئے تھے۔
(۲) مذھب العرب انھم کانوا مطبوعین علی الحفظ مخصوصین بذالک (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۹)
’’عرب کا طریقہ ہی یہ تھا کہ حفظ کی دولت ان کی فطرت اور طبیعت میں پیوست تھی اور وہ اس دولت سے مختص تھے۔‘‘
اس عبارت سے ان کی فطری صلاحیت اور حفظ کے ساتھ اختصاص بالکل واضح ہے۔
(۳) قال الخلیل رحمہ اللہ تعالیٰ ؎
لیس العلم ما حوی القمطر
ما العلم الا ما حواہ الصدر
’’امام خلیل بن احمدؒ (المتوفی ۱۷۴ھ) فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو کاغذوں اور کتابوں میں درج ہے بلکہ علم وہ ہے جو سینہ میں محفوظ ہے۔‘‘
(۴) یونس بن حبیبؒ نے ایک شخص سے سنا (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۹) ؎
استودع العلم قرطاسا فضیعہ
و بئس مستودع العلم القراطیس
’’یعنی اس نے علم کو کاغذ کے سپرد کر دیا اور علم کو ضائع کر دیا اور علم کا برا ظرف اور مکان کاغذ ہیں۔‘‘
(۵) منصور فقیہ فرماتے ہیں (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۹) ؎
علمی معی حیث ما یممت احملہ
بطنی دعاء لہ بطن صندوقی
ان کنت فی البیت کان العلم فیہ معی
او کنت فی السوق کان العم فی السوقٖ
’’یعنی میرا علم میرے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی میں قصد کرتا ہوں اسے اٹھائے پھرتا ہوں۔ میرا پیٹ علم کا برتن ہے نہ کہ صندوق کا پیٹ۔ اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو علم بھی میرے ساتھ گھر میں ہی ہوتا ہے اور اگر میں بازار میں ہوتا ہوں تو علم بھی میرے ساتھ بازار میں ہوتا ہے۔‘‘
(۶) ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب کا حافظہ دیا تھا کہ غیر ارادی طور پر بھی وہ جو کچھ سن لیتے وہ بھی ان کے سینہ میں محفوظ رہتا۔ چنانچہ امام زہریؒ کا بیان ہے کہ
انی لامر البقیع فاسد اذانی مخافۃ ان یدخل فیھا شئ من الخنافوا اللہ ما دخل اذنی شئ قط خفیتہ۔ (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۹)
’’میں بقیع کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں اس ڈر کے مارے کہ میرے کانوں میں کوئی فحش قسم کے گانے نہ داخل ہو جائیں۔ بخدا کبھی کوئی چیز میرے کان میں داخل نہیں ہوئی کہ پھر وہ مجھے بھول گئی ہو۔‘‘
جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے غضب کے حافظے مرحمت فرمائے تھے وہ بھلا اپنے پیارے پیغمبر کی باتوں کو بھول سکتے تھے جب کہ آپؐ کے ایک بال کے متعلق حضرت عبیدہؒ (بن عمرو السلمانیؒ المتوفی ۷۲ھ) یہ فرماتے ہیں:
لان تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا و ما فیھا۔ (بخاری ج ۱ص ۲۹)
’’یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہو تو دنیا و ما فیھا سے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔‘‘
خیال فرمائیں کہ جو حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک کو دنیا و مافیھا سے بہتر سمجھتے تھے وہ آپؐ کی حدیثوں کو کس عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔
(۷) امام ابن عبد البرؒ لکھتے ہیں کہ
ان العرب قد خصت بالحفظ کان احدھم یحفظ اشعار بعض فی سمعۃ واحدۃ وقد جاء ان ابن عباسؓ حفظ قصیدۃ عمر بن ابی ربیعۃ امن آل نعم انت عاد فبکر فی سمعۃ واحدۃ الخ۔ (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۶۹ و ۷۰)
’’اہل عرب حافظہ کے ساتھ مختص تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو ایک ہی دفعہ بعض کے اشعار سن کر یاد کر لیتے تھے اور حضرت ابن عباسؓ نے عمر بن ابی ربیعہ کا قصیدہ امن من آل الخ (یعنی کیا آل نعم سے توکل بہت ہی سویرے چلے گا الخ) ایک ہی دفعہ سن کر یاد کر لیا تھا (یہ قصیدہ تقریبًا ستر یا اسی اشعار پر مشتمل تھا)۔‘‘
(۸) امام شعبیؒ فرماتے ہیں:
ما کتبت سوداء فی بیضاء و ما استعدت حدیثًا من انسان۔ (طبقات ابن سعدؒ دارمی ص ۱۲۵ طبع دمشق و تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۶۷)
’’یعنی میں نے کبھی سیاہی کے ساتھ کاغذ پر کچھ نہیں لکھا (سب سینے میں محفوظ کیا ہے) اور میں نے کبھی کسی انسان سے حدیث دہرانے کی خواہش نہیں کی۔‘‘
یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو دینی ذوق ان حضرات کو تھا وہ بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکا اور قرآن کریم کے بعد دین کا منبع حدیث شریف اور آثار حضرات صحابہؓ ہیں اور حفظ کی خداداد دولت بھی ان کو وافر نصیب تھی اور انہوں نے پوری ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کا ثبوت بھی دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ واٰلہ وسلم کا کوئی قول اور فعل بلکہ کوئی حرکت و ادا ان سے اوجھل نہ رہے تو پھر یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی کی ہو۔ اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت قرآن کریم کے بعد احادیث کی حافظ ہوتی تھی۔ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ حدیثیں ازبر ہوتی تھیں اور ہر مسلمان چلتی پھرتی سنت تھا۔
جب خیر القرون سے بُعد ہوتا گیا تو وہ برکات نہ رہیں جو ان مبارک قرون میں ہوتی تھیں اور علم و عمل کا وہ ذوق و شوق بھی کم ہوتا چلا گیا اور جید اور قابل اعتبار علماءِ ملت کو فکر ہوئی کہ کتب حدیث کی باقاعدہ تدوین کیے بغیر یہ قیمتی ذخیرہ محفوظ اور باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے حدیث کو کتابت کی شکل میں محفوظ رکھنا ضروری سمجھا اور ان کی اس نیک اور مخلصانہ کوشش اور کاوش سے حدیث کی تدوین ہوئی۔
الغرض کتابتِ حدیث تو دورِ زوال و انحطاط کی یادگار ہے اور اس دور کی کارروائی تو منکرینِ حدیث کے نزدیک قابلِ سند اور حجت ہے مگر صد افسوس ہے کہ دورِ کمال اور زمانۂ عروج کی ارفع و معتمد علیہ کارروائی ان کے نزدیک مشکوک ہے اور ان کا یہ عذر لنگ محض حدیث سے رستگاری کے لیے ہے کہ کلیتًا حدیث سے انکار کے بعد دین کی جو صورت ان کے ماؤف ذہن اور نارسا عقل میں آئے گی وہ دین تصور ہو گی ۔۔۔ اور جو کچھ بقول ان کے عقل کے خلاف ہو گا یا ان کے نفسِ امارہ پر شاق اور گراں گزرے گا تو وہ بزعم ان کے عجمیوں کی سازش ہو گی اور ناقابل اعتماد ذخیرہ ہو گا۔ اگر ان کے نزدیک کتابت ہی حجت اور قابل اعتبار حقیقت ہے تو ذیل کے ٹھوس اور مفصل حوالوں سے بخوبی اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ان مبارک ادوار میں کتابت حدیث کی بھی کوئی کمی نہ تھی اور لکھنے والے باقاعدہ لکھا بھی کرتے تھے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل ہدایت نامہ جس میں دین کی بنیادی باتوں کا تذکرہ ہے تحریر کروا کر اور مہر لگا کر بدست حضرت دحیہؓ بن خلیفہ ہرقل روم کو بھیجا تھا (بخاری ج ۱ ص ۴، مسلم ج ۲ ص ۹۷)۔ اور اسی طرح بنام کسرٰی شاہ ایران آپؐ کا دعوت نامہ جو بحرین کے گورنر المنذر بن ساوٰی کی وساطت سے آپؐ نے بھیجا تھا اس کا تذکرہ بخاری ج ۱ ص ۱۵ وغیرہ میں موجود ہے اور مسلم ج ۲ ص ۹۹ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرٰی، قیصر، نجاشی اور ہر جابر کو اللہ تعالیٰ (کے دین) کی طرف دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھ کر بھیجے اور اس روایت میں نجاشی سے مراد وہ نجاشی نہیں جس کا جنازہ آپؐ نے پڑھایا تھا۔ ان کا نام اصحمہؓ تھا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی طرح دیگر بعض بادشاہوں اور مقتدر شخصیتوں کو آپ نے اسلام کے دعوت نامے بھیجے۔
حضرت ابو شاہ یمنی ؓ کی درخواست پر جو خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا وہ آپؐ نے لکھوا کر ان کو دیا تھا اور اسی میں آپؐ کے صریح الفاظ ہیں ’’اکتبولا بی شاہؓ‘‘ کہ یہ ابو شاہؓ کو لکھ کر دو (بخاری ج ۱ ص ۲۲ و ج ۱ ص ۳۲۹ و مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۸)۔
کتبِ حدیث و تاریخ اور سیر پر گہری نگاہ رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ آپؐ کا حجۃ الوداع کا خطبہ کتنا طویل اصول و فروع کے اہم مسائل پر حاوی اور جامع و مانع تھا۔ اگر آپؐ کے ارشادات کا لکھنا ناجائز ہوتا تو آپؐ صاف طور پر فرما دیتے کہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو صرف زبانی طور پر یاد رکھو اور نیز اگر آپؐ کے ارشادات حجت نہ ہوتے تو اولًا حضرت ابو شاہؓ کو ان کے لکھوا کر محفوظ رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، و ثانیًا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے کہ (معاذ اللہ) میری باتیں تو صرف مجمع کو جمع کرنے اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ صرف دماغی اور ذہنی عیاشی ہے تم لکھنے کے بیکار کام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ غرضیکہ ہر حق جو اس سے حقیقت کو پا سکتا ہے اور یہ ایک خالص حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں حضرات صحابہ کرامؓ کے جتنے اجتماعات ہوئے حجۃ الوداع کا اجتماع ان سب سے بڑا، نرالا اور آخری اجتماع تھا۔ اور ابن ماجہ ص ۲۲ کی روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار انسان جمع تھے (بشر کثیر) اور سب یہ چاہتے تھے کہ آپؐ کی پیروی کریں اور آپؐ کے عمل جیسا عمل کریں اور یہی نیک جذبہ ان کو آپؐ کے گرد جمع کیے ہوئے تھا۔
حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک جن حضرات نے آپؐ سے حدیثیں سنیں اور آپؐ کو دیکھا جن میں مرد اور عورتیں سبھی شامل ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی (اصابۃ فی تذکرۃ الصحابۃؓ ج ۱ ص ۳)
حضرت عبد اللہ بن عمروؓ (المتوفی ۶۳ھ) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میرے بغیر کسی کو اتنی حدیثیں معلوم نہیں ۔۔۔۔۔ (حضرت ابوہریرہؓ سے ۵۳۷۴ حدیثیں مروی ہیں) جتنی حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کو معلوم ہیں کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا (بخاری ج ۱ ص ۲۲ و ترمذی ج ۲ ص ۲۲۴ و دارمی ص ۶۷ و مستدرک ج ۱ ص ۱۰۵)۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کا حدیثیں نہ لکھنے (اور نہ لکھوانے) کا واقعہ ابتدائی دور کا ہے، آخر میں حضرت ابوہریرہؓ سے کتابتِ حدیث کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر الحسن بن عمروؒ بن امیہؓ سے سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ کے پاس ایک حدیث بیان کی گئی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی لکھی ہوئی کتابیں دکھلائیں اور فرمایا کہ یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہیں۔
امام ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ ہمام کی روایت (جس میں عدم کتابت کا ذکر ہے) زیادہ صحیح ہے اور دونوں روایتوں میں جمع اور تطبیق بھی ممکن ہے۔ وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں وہ نہیں لکھتے تھے اور پھر بعد کے زمانہ میں لکھتے تھے (فتح الباری ج ۱ ص ۲۱۷)۔ حضرت ابوہریرہؓ کے ایک مجموعہ کا جو مروان نے حکمتِ عملی سے لکھوایا تھا اور جس میں بہت سی حدیثیں درج تھیں ذکر پہلے ہو چکا ہے اور ان کی کچھ احادیث کا مجموعہ حضرت ہمامؒ بن منبہؒ نے تیارکیا تھا جو صحیفۂ ہمامؒ کے نام سے احادیث میں مشہور ہیں، اس سے کچھ حدیثیں حضرت امام احمدؒ نے مسند ج ۲ ص ۳۴ تا ص ۳۱۸ میں نقل کی ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں و صحیفۃ ہمام مشہورۃ (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۱۶) کہ ہمامؒ کا صحیفہ مشہور ہے۔ اور اسی طرح حضرت بشیر بن نہیکؒ نے بھی حضرت ابوہریرہؓ کی روایتوں کا ایک مجموعہ لکھا ہے اور پھر ان سے اس کی روایت کی اجازت بھی لی (کتاب العلل ترمذی ج ۲ ص ۲۳۹ و دارمی ص ۶۸)
مولانا عزیر گلؒ
تحریک شیخ الہندؒ کی آخری یادگار
عادل صدیقی
حضرت شیخ الہندؒ کے خادم خاص، انتہائی خطرناک اور جوکھم کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے سے طبعًا مناسبت رکھنے والے، صوبہ سرحد اور آزاد علاقہ یاغستان میں وطنِ عزیز کی آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے، رازداری اور بلند ہمتی کے پیکر جلیل، دوسروں کے لیے خدمت گزاری کا جذبہ رکھنے والے، دوسروں کو راحت اور خود تکلیف اٹھانے میں مسرت محسوس کرنے والے، حق رفاقت کے آداب نبھانے والے، ملکوتی شخصیتوں کے رازداں بننے کی پوری صلاحیت رکھنے والے، دورِ شباب میں ہی آزادیٔ وطن کی خاطر سر اور دھڑ کی بازی لگانے والے، انتہائی جری، بہادر اور غیرت مند، سوجھ بوجھ کے سمندر کے تیراک، صاف گوئی اور بے باکی میں لاجواب انسان حضرت مولانا عزیر گلؒ نے تقریباً ایک سو دس سال کی زندگی گزار کر اس دارفانی سے کوچ کیا۔ آپ کا انتقال اپنے آبائی وطن ایجنسی مالاکنڈ پشاور میں ہوا۔
سی آئی ڈی کی رپورٹ کے مطابق آپ کا وطن درگئی ہے لیکن آپ کا آبائی وطن زیارت کاکا صاحب (پشاور) تھا، البتہ آپ کے والد بزرگوار نے درگئی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی اور اس کے بعد آپ کو دین کی تعلیم کے حصول کے لیے دنیا کی شہرہ آفاق یونیورسٹی ’’مدرسہ دارالعلوم دیوبند‘‘ میں بھیجا گیا۔ آپ کا ابتداء میں ہی رابطہ حضرت شیخ الہندؒ سے ہو گیا تھا اور پھر یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ زندگی بھر نہ ٹوٹا۔ مولانا عزیرگلؒ اپنی سادگی طبع کی وجہ سے اساتذہ کے حلقہ میں بے حد مقبول تھے۔
آپ نے جس دور میں پرورش پائی وہ ہندوستان میں انگریزوں کی سامراجی پالیسی کے خلاف علماء ہند اور بالخصوص علماء دیوبند کی جدوجہد کا زمانہ تھا۔ حضرت شیخ مولانا محمود حسنؒ نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے اور آزادی سے ملک کو ہمکنار کرنے کا نعرہ ایسے وقت بلند کیا جبکہ یہاں اس بات کو سوچنا مصائب اور موت کو دعوت دینا تھا۔ یہ انگریزوں کی سلطنت کا عروج تھا اور اس دور میں زمیندار اور امراء انگریزوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ایسے دور میں انگریزوں کی مخالفت کرنا اور ملک کی آزادی کے بارے میں سوچنا ایسے ہی سرپھرے لوگوں کا کام ہو سکتا تھا جو باطن کی نگاہ رکھتے ہوں اور جن کی ملی غیرت ان کو انگریزوں کا غلام بننے سے روکتی ہو۔ چنانچہ حضرت شیخ الہندؒ سے درس حاصل کرنے کے دوران ان میں جذبۂ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھر چکا تھا، پھر سونے پر سہاگہ یہ کہ آپ کو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ جیسا رفیق ملا۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ تحریر فرماتے ہیں:
’’مولانا عزیر گل صاحب، حضرت شیخ الہندؒ کے خادم خاص ہیں۔ مشن کے ابتدا سے ممبر رہے اور نہایت مہتم بالشان اور خطرناک کاموں کو انجام دیتے رہے۔ صوبہ سرحد اور آزاد علاقہ یاغستان میں سفارت کی خدمات عظیم انہوں نے انجام دیں۔ عمومًا شیخ الہندؒ ان کو پہاڑی علاقوں میں اپنے ہم خیال اور ہمنوا لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ دشوار گزار اور خطرناک راستوں کو قطع کر کے نہایت رازادی اور ہمت و استقلال کے ساتھ بار بار آتے جاتے رہے۔ پہاڑی علاقوں اور ہولناک جنگلوں کو رات دن پیدل قطع کرتے رہے۔ حاجی ترنگ زئی اور علماء سرحد یاغستان اور دیگر خواتین کو آپ نے مشن کا ممبر بنایا۔ ان کے پاس پیغام اور خطوط پہنچانا، ان کو ہموار کرنا، ان کا اور مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم کا فریضہ تھا جن کو ان دونوں حضرات نے اوقاتِ مختلفہ میں انجام دیا۔ باوجودیکہ سی آئی ڈی ان کے پیچھے لگی رہی مگر انہوں نے کبھی اس کا پتہ چلنے نہ دیا۔ باربار ان کو بھیس بدلنا پڑا اور انجان علاقوں سے گزرنا پڑا مگر نڈر ہو کر ان کو قطع کیا۔ ہر قسم کے خطرات میں بلاخوف و خطر اپنے آپ کو ڈالتے رہے۔‘‘
جب سلطنتِ برطانیہ نے حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک سے واقفیت حاصل کی تو اس نے حضرت کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا۔ جب اس طرح کی خبریں حضرت شیخ الہندؒ کو معلوم ہوئیں تو حضرت حجاز کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ شریف حسین نے مکہ معظمہ میں سلاطین آل عثمان کی خلافت سے انکار کیا اور ترکی قوم کی تکفیر کا فتوٰی بہت سے علماء سے حاصل کیا۔ اس زمانے میں جب یہ فتوٰی حضرت شیخ الہندؒ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری کارروائی انگریزوں کے ایماء پر ہوئی تھی اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ شریف مکہ کو حضرت شیخ الہندؒ کے خلاف کھڑا کیا جا سکے اور پھر شریف حسین کے ذریعے حضرت شیخ الہندؒ کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نے درمیان میں پڑ کر صلح صفائی کی کوشش فرمائی مگر یہ بے سود رہی۔ یہی نہیں سب سے پہلے حضرت حسین احمد مدنیؒ کو گرفتار کر لیا گیا۔ شریف مکہ کے پاس بہت سے تاجر پہنچے اور کہا کہ شیخ الہندؒ کی گرفتاری کا ارادہ ترک کر دیا جائے مگر شریف مکہ کے دل میں غبار تھا۔ اس نے کہا کہ انگریزوں سے دوستی قائم رکھنے کے لیے حضرت کی گرفتاری ضروری ہے۔ جب یہ معلوم ہوا تو حضرت شیخ الہندؒ کو چھپا دیا گیا مگر مولانا عزیر گلؒ سے، جو اس وقت شیخ الہندؒ کے ساتھ ہی وہاں گئے ہوئے تھے، حضرت شیخ الہندؒ کا پتہ دریافت کیا گیا اور یہ دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے پتہ نہ بتایا تو ان کو گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ حضرت شیخ الہندؒ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خود ہی باہر آ گئے اور فرمایا کہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے باعث میرے دوست کا بال بیکا ہو۔ احباب کے کہنے پر آپ نے احرام باندھا اور کہا کہ احرام باندھنے کی خاطر باہر گئے تھے مگر حضرت شیخ الہندؒ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں سے یہ حضرات جدہ بھیج دیے گئے اور وہاں سے مصر کے لیے روانہ کر دیے گئے اور ۱۵ فروری ۱۹۱۷ء کو وہاں سے یہ حضرات مالٹا چلے گئے جو سیاسی اور جنگی قیدیوں کا مرکز تھا۔
ہندوستان سے مکہ معظمہ کی روانگی، وہاں قیام اور پھر وہاں سے مالٹا میں قیدی بنا کر بھیج دینے کے دوران مولانا عزیرگلؒ حضرت شیخ الہندؒ کے رفیق خاص تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ تحریر فرماتے ہیں:
’’مولانا عزیر گل خادم خاص کو اپنے وطن جانا اور اپنے اکابر سے ملنا اور اجازت چاہنا ضروری تھا اس لیے ان کی واپسی کا انتظار فرمایا۔ قید کے دوران مولانا عزیر گل کا خیال تھا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی۔۔۔۔۔ مولوی عزیر گل تو اپنی کوٹھڑی میں رہ کر اپنی گردن اور گلے کو پھانسی کے لیے ناپتے اور دباتے تھے کہ ذرا مہارت ہو جائے اور پھانسی کے وقت یکبارگی تکلیف سخت نہ پیش آئے اور تجربہ کرتے تھے کہ دیکھوں کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے مگر سب کے دل مطمئن تھے گویا کہ نانی کے گھر میں آرام کر رہے ہوں۔‘‘
قید میں رہتے ہوئے مولانا عزیر گلؒ نے قرآن شریف حفظ کرنے کی کوشش کی اور ترکی زبان سیکھی۔ مولانا عزیر گل جس طرح دیوبند میں حضرت شیخ کے خادم خاص تھے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور اسارتِ مالٹا میں بھی خادمِ خاص رہے۔ دیوبند واپس آئے تو آپ کا مسکن وہ مکان تھا جس میں اس وقت حضرت شیخ الہندؒ کی بھانجی کی اولاد رہتی ہے۔ آپ کی شادی دیوبند میں سابق صدر مدرس فارسی مولانا محمد شفیع حسین کی بہن سے ہوئی تھی اور ان سے دو لڑکے ہیں، ایک کا نام محمد زبیر ہے جنہیں عبد الرؤف بھی کہتے ہیں، دوسرے کا نام محمد زہیر ہے، دو لڑکیاں ہیں جو صاحبِ اولاد ہیں۔
مولانا عزیر گلؒ کی وفات سے نہ صرف ایک عظیم مجاہدِ آزادی اس دنیا سے چل بسا بلکہ حضرت شیخ الہندؒ کی یادگار کی آخری کڑی بھی الٹ گئی ؏
خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را
(بشکریہ دیوبند ٹائمز)
مجھے قرآن میں روحانی سکون ملا
ایک نومسلم کنیڈین خاتون کے تاثرات
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
گزشتہ روز امریکہ سے ایک نومسلم خاتون ڈاکٹر مجاہدہ کے ہرمینسن گوجرانوالہ تشریف لائیں، ان کا سابقہ نام مارسیا ہے اور امریکی ریاست کیلی فورنیا میں سن ڈیگوسٹیٹ یونیورسٹی کے شعبہ مذہبی امور کی پروفیسر ہیں۔ان کے خاوند ملک محمد علوی ان کے ہمراہ تھے۔ علوی صاحب وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ کے رہنے والے ہیں اور پندرہ سال سے امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ ڈاکٹر مجاہدہ پیدائشی طورپر کنیڈین ہیں اور ایک عرصہ سے امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ موصوفہ نے کم وبیش دس سال قبل اسلام قبول کیا، عربی زبان سیکھی، ار دو اور فارسی سے بھی آشنائی حاصل کی،امام ولی اللہ دہلویؒ کے مذہبی نظریات پر برکلے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور ان دنوں تذکرہ نویسی کے موضوع پر اپنے ایک مقالہ کی تیاری کے لیے سکالرشپ پر پاکستان آئی ہوئی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ پر پی ایچ ڈی کے مقالہ کی تیاری کے دوران انہیں حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب مہتمم مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کی بعض تصانیف سے استفادہ کا موقع ملا اور اپنے دورۂ پاکستان کے موقع پر انہیں یہ شوق ہوا کہ حضرت صوفی صاحب مدظلہ سے براہ راست ملاقات کریں اور ان سے علمی استفادہ کریں۔
۱۷ فروری کو مدرسہ نصرۃ العلوم کی لائبریری میں ڈاکٹر مجاہدہ موصوفہ کی حضرت صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں ملک محمد علوی صاحب اور راقم الحروف بھی شریک تھے۔ اس موقع پر حضرت صوفی صاحب نے ڈاکٹر مجاہدہ سے سوال کیا کہ آج کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی اجتماعی حالت باعث کشش نہیں ہے انہیں اسلام کی طرف رغبت کیسے ہوئی اور انہوں نے کس چیز سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ ڈاکٹر مجاہدہ نے جواب دیا کہ انہیں ایک عرصہ سے روحانی سکون کی تلاش تھی اور وہ روحانی طورپر ایک خلا محسوس کررہی تھی، روح کے لیے سکون کی تلاش میں انہوں نے متعدد سفر کیے، اس دوران جبکہ وہ سپین (اندلس) میں تھیں مراکش ریڈیو سے انہیں متعدد بار قرآن کریم کی تلاوت سننے کا موقع ملا اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ جس روحانی سکون کی تلاش میں ہیں وہ اس کلام میں ہے۔ انہیں عربی زبان سے بھی دلچسپی تھی اس لیے انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور قرآن کریم کے اس مطالعہ نے انہیں ہدایت کی منزل سے ہمکنار کردیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک موقع پر دہلی میں تھیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالٰی کے مزار پر گئیں وہاں انہوں نے ایک عجیب قسم کے روحانی سکون کی فضا محسوس کی جس سے انہیں تصوف اور سلوک سے دلچسپی پیدا ہوئی۔
ڈاکٹر مجاہدہ نے بتایا کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی معروف تصنیف ’’حجۃ اللہ البالغۃ‘‘ کا انگلش میں ترجمہ شروع کیا ہے، ایک جلد کا ترجمہ وہ مکمل کرچکی ہیں اور دوسری جلد پر کام جاری ہے۔ نیز انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہؒ پر چوتھا مقالہ لکھا ہے جسے ’’حجۃ اللہ البالغۃ‘‘ کے انگلش ترجمہ کے مقدمہ کے طور پر شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے انگلش میں حضرت شاہ ولی اللہؒ پر چند مقالات لکھے ہیں جو مختلف جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔
حضرت صوفی صاحب مدظلہ کے ساتھ ایک گھنٹہ کی یہ نشست انتہائی معلوماتی اور ایمان افروز تھی۔ نو مسلم کنیڈین خاتون نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفہ اور جدوجہد کے مختلف پہلوؤں پرسوالات کیے جن پر حضرت صوفی صاحب مدظلہ نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر مجاہدہ حضرت صوفی صاحب سے شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفہ اور کام پر گفتگو کر رہی تھیں اور میرا ذہن اس سوال کے گرد گھوم رہا تھا کہ اسے اسلام کا اعجاز کہاجائے یا شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کرامت کہ اللہ رب العزت دہلی سے ہزارہا میل دور کیلی فورنیا کی ایک یونیورسٹی میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفہ اور تعلیمات کی اشاعت اور تعارف کا ایک ایسے دور میں انتظام کر رہا ہے جبکہ دنیا کا معاشرہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کی دی ہوئی مادرپدر آزادی اور کمیونزم کے مسلط کردہ اجتماعی جبر کی حشر سامانیوں سے تنگ آچکا ہے، اور کسی ایسے معتدل اور متوازن نظام کی تلاش میں ہے جو بے راہ روی اور جبر کے درمیان صراط مستقیم کی حیثیت رکھتا ہو۔ یہ نظام بلاشبہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے اور اسے جس طرح انسانی معاشرے کے لیے اجتماعی نظام کے طورپر شاہ ولی اللہؒ نے پیش کیا ہے یقیناً وہی فلسفہ مغربی جمہوریت، کیپٹل ازم اور کمیونزم کا نظریاتی طور پر سامنا کر سکتا ہے اور وہ وقت قریب آگیا ہے جب ولی اللہی فلسفہ ایک زندہ اور متحرک قوت کے طور پر نظام اسلام کے احیاء ونفاذ کا ذریعہ بنے گا، ان شاء اللہ العزیز۔
ڈاکٹر مجاہدہ کو ’’شاہ ولی اللہ یونیورسٹی‘‘ کے منصوبہ سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر بے حد مسرت کا اظہار کیا اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کی کامیابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس منصوبہ کے لیے ان سے جس قسم کی تعاون کی ضرورت ہوگی وہ اس میں خوشی اور سعادت محسوس کریں گی۔
نظامِ خلافت کا احیاء
امت کے مسائل کا واحد حل
مولانا ابوالکلام آزاد
انتخاب و ترجمہ: مولانا سراج نعمانی، نوشہرہ صدر
(جناب ابو سلمان شاہجہانپوری کی کتاب ’’تحریکِ نظمِ جماعت‘‘ سے انتخاب)
اجتماعیت کا حکم
اسلام نے مسلمانوں کے تمام اعمالِ حیات کے لیے بنیادی حقیقت یہ قرار دی ہے کہ کسی حال میں بھی فرادٰی، متفرق، الگ الگ اور متشتت نہ ہوں، ہمیشہ موتلف، متحد اور کَنَفْسٍ وَّاحِدَۃٍ ہو کر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں جابجا اجتماع و وحدت پر زور دیا گیا ہے۔ اور کفر و شرک کے بعد کسی بدعمل سے بھی اس قدر اصرار و تاکید کے ساتھ نہیں روکا جس قدر تفرقہ و تشتت سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام و اعمال میں یہ حقیقت اجتماعیہ بمنزلہ مرکز و محور کے قرار پائی اور ۔۔۔۔اسی لیے نظمِ اقوامِ ملت کے لیے منصبِ خلافت کو ضروری قرار دیا گیا کہ تمام متفرق کڑیاں ایک زنجیر میں منسلک ہو جائیں۔ (ص ۲۴)
اعمال کی اقسام
اعمالِ شریعت دو قسم کے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی سے مقصود وہ اعمال ہیں جن کو الگ الگ ہر فرد انجام دے سکتا ہے جیسے نماز، روزہ۔ اجتماعی سے مقصود وہ اعمال ہیں جن کی انجام دہی کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، الگ الگ ہر فرد انجام نہیں دے سکتا جیسے جمعہ ۔۔۔ مثلاً جمعہ کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہ ہو گا کہ ادائے جمعہ کا طریقہ بتلا دیا جائے بلکہ جماعت کا انتظام بھی کرنا چاہیئے تاکہ جمعہ عملاً انجام پا سکے۔ گویا پہلی قسم کے (انفرادی) (ناقل) اعمال کی تبلیغ کے لیے اس قدر کافی ہے کہ ان کے وجوب و عمل کا حکم دے دی جائے اور بتلا دیا جائے کہ لوگ اس طرح انجام دیں۔ لیکن دوسری قسم کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے، حصول و قیام کا بھی انتظام کرنا چاہیئے کیونکہ انفرادًا وہ اعمال انجام نہیں پا سکتے جب تک جماعت کا انتظام نہ ہو جائے مثلاً جمعہ۔۔۔ (ص ۲۹۱)
ہندوستانی مسلمانوں کی حالت
دس کروڑ مسلمان جو کرۂ ارض میں سب سے بڑی یکجا اسلامی جماعت ہے ہندوستان میں اس طرح زندگی بسر کر رہی ہے کہ نہ تو اس میں کوئی رشتہ انسلاک ہے نہ وحدتِ ملت کا کوئی رابطہ ہے نہ کوئی قائد و امیر ہے۔ ایک انبوہ ہے ایک گلہ ہے جو ہندوستان کی آبادیوں میں بکھرا ہوا ہے اور یقیناً ایک حیاتِ غیر شرعی و جاہلی ہے جس میں پوری اقلیم مبتلا ہو گئی ہے۔
بھیڑ اور جماعت میں فرق
پہلی چیز (بھیڑ) بازاروں میں نظر آتی ہے جب کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ دوسری چیز جمعہ کے دن مسجدوں میں دیکھی جا سکتی ہے جب ہزاروں انسانوں کی منظم و مرتب صفیں ایک مقصد، ایک جہت، ایک حالت اور ایک ہی (امام) کے پیچھے جمع ہوتی ہیں ۔۔۔۔ شریعت نے مسلمانوں کے لیے جہاں انفرادی زندگی کے اعمال مقرر کیے ہیں وہاں ان کے لیے اجتماعی نظام بھی قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتی ہے زندگی اجتماع کا نام ہے۔ افراد و اشخاص کوئی شے نہیں۔ جب کوئی اس نظام کو ترک کر دیتی ہے تو گو اس کے افراد فردًا فردًا کتنے ہی شخصی اعمال و طاعات میں سرگرم ہوں لیکن یہ سرگرمیاں اس بارے میں کچھ سودمند نہیں ہو سکتیں اور قوم ’’جماعتی معصیت‘‘ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت نے بتلا دیا ہے کہ شخصی زندگی کے معاصی کسی قوم کو یکایک برباد نہیں کرتے۔ اشخاص کی معصیت کا زہر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے لیکن جماعتی معصیت کا غم ایسا تخمِ ہلاکت ہے جو فورًا بربادی کا پھل لاتا ہے اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ شخصی اعمال کی اصلاح و درستگی بھی نظامِ اجتماعی کے قیام پر موقوف ہے۔ مسلمانانِ ہند جماعتی زندگی کی معصیت میں مبتلا ہیں اور جب جماعتی معصیت سب پر چھا گئی تو افراد کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے؟ (ص ۳۰)
جماعتی زندگی کی معصیت
جماعتی زندگی کی معصیت سے مقصود یہ ہے کہ ان میں ایک جماعت بن کر رہنے کا شرعی نظام مفقود ہو گیا ہے۔ وہ بالکل اس گلے کی طرح ہیں جس کا انبوہ جنگل کی جھاڑیوں میں منتشر ہو کر گم ہو گیا ہو۔ وہ بسا اوقات یکجا ہو کر اپنی جماعتی زندگی کی نمائش کرنا چاہتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں، کانفرنسں منعقد کرتے ہیں لیکن یہ تمام اجتماعی نمائشیں شریعت کی نظر میں بھیڑ اور انبوہ کا حکم رکھتی ہیں، جماعت کا حکم نہیں رکھتی۔ (ص ۲۸)
دین کامل
اسلام کا اعلان ہے کہ دین کامل ہو چکا ’’اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینْکَمُ‘ْ‘ اور دین کامل وہی ہے جو اپنے پیروؤں کی ہر عہد اور ہر حالت میں رہنمائی کر سکے۔ پس اگر اسلام مسلمانوں کو ایسے اہم اور بنیادی معاملے (اتفاق و اجتماعیت) میں یہ بھی نہیں بتلا سکتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیئے؟ حتٰی کہ وہ مہینوں سرگرداں و حیران رہتے ہیں، پے در پے مشوروں کے جلسے کرتے ہیں، متحیر ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں اور پھر مجبور ہوتے ہیں کہ کسی غیر شرعی تجویز پر کاربند ہونے کا اعتراف کر لیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے مائگی و تہی دستی اور نقصِ شریعت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ (ص ۲۹۳)
یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اسلام مسلمانوں کو روزانہ ضروریات و اعمال کی چھوٹی چھوٹی باتیں تک بتلا دے لیکن یہ نہ بتلا سکے کہ چھ کروڑ انسان اپنا ایمان کیونکر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پس اگر خلافت کا مسئلہ دینی مسئلہ ہے تو اس کی جدوجہد کی ہر منزل کے لیے شریعت کے احکام کو بھی بالکل اسی طرح صاف اور واضح ہونا چاہیئے جیسے ’’اَقِیْمُوا الصَّلوٰۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ‘‘۔ اگر کہا جائے کہ احکام ہم کو معلوم ہیں مگر ہندوستان میں ہماری حالت ایسی مجبوری اور بے بسی کی ہے کہ ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ مجبوری دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا واقعی ہے یا غیر واقعی۔ اگر واقعی نہیں ہے تو وہ عذر ہی نہیں اور واقعی ہے تو خدا کی شریعت عادلہ انسان کی فلاح و صلاح کے لیے ہے ۔۔۔۔ اس نے ہر حالت کے لیے حکم دیے ہیں اور ہر طرح کے عذروں کی پذیرائی کی ہے اور ہر قسم کے حالات و مقتضیات کی راہیں باز رکھی ہیں۔ طہارت کے لیے وضو کا حکم دیا ہے لیکن اگر عذر پیش آجائے تو معذور کے لیے تیمم کا حکم بھی موجود ہے۔ معذور کے لیے تیمم کا عمل ویسا ہی صحیح و کامل ہے جیسے غیر معذور کے لیے وضو۔ پس اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو واقعی عذرات درپیش ہیں تو عذرات کی صورت میں بھی مثلِ حکمِ تیمم کے کوئی حکم ہونا چاہیئے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اس کو بتلایا جائے اور (اس پر) عمل کرنا چاہیئے۔
مسلمان حکومت و سلطنت سے تہی دست ہو جائیں لیکن خدا کے لیے اسلام کو راہنمائی و ہدایت سے تہی دست ثابت نہ کرو۔ چھ کروڑ مسلمانوں میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہ رہا جو اسلام کے نورِ علم و ہدایت سے اس ظلمت و کورئ ملت کو دور کر سکے اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر بلا سکے کہ ’’عَلٰی بَصِیْرَۃٍ اَنَا وَ مَنِ اتَبَعَنِیْ ‘‘۔ کیا اسلام کی قوتِ تعلیم و تربیت اب اس قدر نامراد ہو گئی ہے کہ نکموں کی اس پوری اقلیم میں ایک بھی کام کا انسان پیدا نہیں کر سکتی۔ کسی زمانے میں ہر دوسرا مسلمان راہنما ہوتا تھا، کیا اب پورے چھ کروڑ مسلمانوں میں ایک بھی ایسا شریعت دان نہیں جو ازروئے شریعت لوگوں کی راہنمائی کر سکے؟ ’’اَلَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیْدٌ‘‘۔ (ص ۲۹۶)
وقت کا تقاضا
آج وقت کی سب سے بڑی اور ادائے فرضِ اسلامی کی سب سے نازک اور فیصلہ کن گھڑی ہے جو آزادیٔ ہند اور مسئلہ خلافت کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان ہیں۔۔۔فی الحقیقت احکامِ شرع کی رو سے مسلمانانِ ہند کے لیے صرف دو ہی راہیں تھیں اور اب بھی دو ہی راہیں ہیں۔ یا تو ہجرت کر جائیں یا نظامِ جماعت قائم کر کے ادائے فرضِ ملت کے لیے کوشاں ہوں۔ (ص ۲۸)
احکامِ شریعت پر کامل ۳۵ برس تک میں نے پوری طرح غور و خوض کیا اور اس ۳۵ سال کے عرصے میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس کی کوئی صبح کوئی شام اس فکر سے خالی گزری ہو۔ بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واضع شریعت کا منشا یہ ہے کہ اس کے احکام یک جماعتی نظام کے تحت اجراء پائیں، لیکن مسلمانوں نے اس جماعتی نظام کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ (ص ۹۴)
حرکۃ المجاہدین کا ترانہ
سید سلمان گیلانی
۲۱ دسمبر ۱۹۸۹ء کو میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ کے جناح ہال میں منعقدہ افغانستان کے مختلف محاذوں پر جہاد میں شریک نوجوانوں کی تنظیم ’’حرکۃ المجاہدین‘‘ کے جلسۂ عام میں سید سلمان گیلانی نے یہ ترانہ پیش کیا۔
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
عَلم اٹھا قدم بڑھا، نہ غیرِ حق سے خوف کھا
تیری مدد کرے خدا، خدا پہ تو بھی رکھ یقیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
نہ کوئی عذرِ لنگ کر، تو کافروں سے جنگ کر
زمین ان پر تنگ کر، نہ مل سکے اماں کہیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
لگا وہ ضرب کفر پر، اٹھا سکے نہ پھر وہ سر
مٹے گا ایک روز شر، کہ خیر کا ہے تو امیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
نجیب سے نہ بات کر، اٹھ اس سے دو دو ہاتھ کر
رسید ایک لات کر، گرے گا یونہی یہ لعیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
تو حوصلے بحال کر، تو کفر سے قتال کر
نہ کوئی قیل و قال کر، یہ سوچنے کی جا نہیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
تو حق کی ترجمان ہے، تو دیں کی پاسبان ہے
جو تیرا نوجوان ہے، وہ جرأتوں کا ہے امیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
حیات کیا ممات کیا، یہ پوری کائنات کیا
نہیں خدا کے ہاتھ کیا، تو پھر یہ کیوں چناں چنیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
تو عہدِ رب پر رکھ نظر، کٹے جو راہِ حق میں سر
بہشت اس کا ہے ثمر، ہے صاف آیتِ مبیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
کہاں غلط یہ بات ہے، خلیل تیرے ساتھ ہے
خدا کا تجھ پہ ہاتھ ہے، تو اس کے در پہ رکھ جبیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
پیامِ حق سنائے جا، ترانہ میرا گائے جا
یہ کفر کو بتائے جا، کہ یہ ہے طرزِ مومنیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
خدا کا لطف عام ہو، جہاں میں اونچا نام ہو
تجھے میرا سلام ہو، مجاہدین کی سرزمیں
حرکۃ المجاہدین، آفرین و آفرین
عیسائی مذہب کیسے وجود میں آیا؟
حافظ محمد عمار خان ناصر
عیسائیوں کی کتب مقدسہ کے مجموعہ کو ’’بائیبل‘‘ کہا جاتا ہے۔ یہ دو اجزاء میں منقسم ہے۔ ایک کو عہد نامہ قدیم (اولڈ ٹسٹامنٹ) اور دوسرے کو عہد نامہ جدید (نیو ٹسٹامنٹ) کہا جاتا ہے۔ اہلِ اسلام کے ایمان کے مطابق حضرت عیسٰی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ’’انجیل‘‘ نام کی ایک کتاب نازل کی تھی اس نے شریعت موسویٰ ؑ کے احکام میں تبدیلیاں کیں (سورہ آل عمران ۵۰)۔ آج کی اناجیل اربعہ (متی، لوقا، مرقس اور یوحنا) اور دیگر کسی بھی موجودہ انجیل کو ’’اصل انجیل‘‘ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ تمام تحریریں حضرت مسیح ؑ کی سوانح عمری پر مشتمل ہیں۔ پادری ولیم میچن لکھتے ہیں کہ:’’اناجیل اربعہ ۔۔۔۔۔ میں جناب مسیح کی سوانح عمری اور تعلیم مرقوم ہے‘‘۔ (رسالہ تحریف انجیل و صحت انجیل ص ۵)
اور ’’المنجد فی الاعلام‘‘ کا عیسائی مصنف انجیل کا تعارف یوں کرواتا ہے:
والاناجیل مجموعۃ اعمال المسیح واقوالہ۔ (ص ۳۸)
’’اناجیل مسیح ؑ کے اقوال و اعمال (سوانح عمری) کا مجموعہ ہیں۔‘‘
ہمارا اعتقاد ہے کہ عیسائیوں کی موجودہ اناجیل قرآن کی تصدیق کردہ انجیل نہیں ہیں۔ مسیحیوں کے موجودہ عقائد حقائق سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ہم مذہب مسیحی ؑ اور اناجیل پر ایک نظر ڈال لیں۔
عیسائی مذہب کا بانی کون؟
عیسائیوں کا یہ دعوٰی غلط ہے کہ عیسائی مذہب کے بانی حضرت مسیح ؑ ہیں۔ درحقیقت اس مذہب کا بانی ’’پولوس‘‘ ہے۔ عہد جدید میں چودہ خطوط اس کے نام منسوب ہیں۔ یہ شخص ایک یہودی تھا جو کافی عرصہ عیسائیوں کو تکلیف اور ایذا دینے کے بعد حضرت مسیح ؑ پر ایمان لے آیا، یہ حضرت مسیح ؑ کا باقاعدہ شاگرد نہیں تھا۔ چنانچہ پادری جے جے لوکس اعتراف کرتے ہیں کہ:
’’وہ اور رسولوں کی مانند مسیح کے ساتھ نہیں رہا، نہ مسیح سے اوروں کی طرح تعلیم پائی، نہ دوسرے رسولوں کی طرح بلایا گیا‘‘۔ (کرنتھیوں کے پہلے خط کی تفسیر مطبوعہ ۱۹۵۸ تفسیر ص ۲)
اس صورتِ حال میں چاہیئے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لانے کے فورًا بعد حضرت مسیح ؑ کے نائبوں کے پاس جاتا اور ان سے تعلیم و تربیت پاتا لیکن ہوا یہ کہ ایمان لانے کے فورًا بعد تین سال کے لیے عرب چلا گیا اور وہاں سے واپس آ کر یروشلم میں صرف پندرہ دن پطرس کے پاس رہا اور پھر تبلیغ کے لیے نکل کھڑا ہوا اور عوام میں بلند ترین مقام حاصل کرنے میں بہت جلد کامیاب ہو گیا۔ اپنی مقبولیت کے ضمن میں لکھتا ہے:
’’تم نے ۔۔۔۔ خدا کے فرشتہ بلکہ مسیح یسوع کی مانند مجھے مان لیا ۔۔۔۔ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے‘‘۔ (گلتیوں ۴: ۱۴ و ۱۵)
اب اس شخص نے کیا کیا؟ ایسے ایسے گمراہ کن عقائد مسیحیت میں داخل کر دیے جن کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔ الوہیت مسیح، موروثی گناہ، کفارہ وغیرہ کا ذکر سب سے پہلے اس کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ پادری جے پیٹرسن اسمتھ کا یہ جملہ نہایت قابل غور ہے کہ
’’سب سے پہلے مسیحی صحیفے پولوس کے خطوط تھے‘‘ (حیات و خطوط پولس مطبوعہ ۱۹۵۲ء ص ۱۳۸)
اور اسی مصنف کی اس صفحہ پر تصریح ہے کہ پولوس کے خطوط لکھنے کا سلسلہ ۵۰ء میں شروع کیا جا چکا تھا اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ:
’’ہماری اناجیل میں سے ایک بھی کتاب اس وقت سے بیس سال تک ضبطِ تحریر میں نہ آئی‘‘۔ (ایضًا)
یہودیت ایک محدود اور نسلی مذہب تھا۔ حضرت عیسٰی ؑ کی بعثت کا مقصد صرف بنی اسرائیل کو ہدایت کرنا تھا، چنانچہ آپ کا فرمان انجیل متی میں یوں مرقوم ہے کہ:
’’میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا‘‘۔ (۱۵: ۲۴)
یہ رہا اناجیل مروجہ اور مسیحی علماء کا موقف جو انجیل برنباس میں مرقوم ہے:
’’میں نہیں بھیجا گیا مگر صرف اسرائیل کی قوم کی جانب‘‘۔ (۲۱: ۲۱)
قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ کی نبویت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی(آل عمران ۹)
مسیح ؑ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ:
’’غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا‘‘۔ (متی ۱۰: ۶)
اور پادری لینڈرم لکھتے ہیں:
’’مسیح نے خود صرف بنی اسرائیل کے لیے کام کیا اور اپنی دنیاوی زندگی کے وقت اپنے شاگردوں کو صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا‘‘۔ (مسیحی تعلیم کا خلاصہ مصنفہ پادری رابرٹ اے لینڈرم، مترجمہ پادری ولیم میچن، مطبوعہ ۱۹۲۶ء ص ۱۲۳)
ادھر پولوس نے دین مسیح کے نام پر غیر اقوام کو تعلیم دی۔
’’تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو‘‘۔ (گلتیوں ۳: ۲۶ و ۲۷)
جن غیر یہودیوں کو مسیح ؑ کتا (انجیل متی ب ۱۵) اور کتے کو ان سے افضل (انجلی برنباس ۲۲: ۲) بتا رہے ہیں وہ سب مسیح میں ایک ہو گئے، سارے امتیازات رفع ہو گئے۔ پادری واکر صاحب کا یہ قول بھی سند کو مضبوط تر کر دیتا ہے کہ:
’’مسیحی جماعت کے لیے خطرہ تھا کہ وہ محض ایک یہودی فرقہ نہ بن جائے لیکن پولس کی کوششوں سے عالمگیر کلیسیا بن گئی‘‘۔ (تفسیر بر اعمال کی کتاب، مطبوعہ ۱۹۵۹ء ص ۲۳)
ایک جانب تو پولس نے کلیسیا کو عالمگیر بنایا، دوسری جانب اس نے ایک اور گُل بھی کھلایا۔ مسیح علیہ السلام شریعت موسوی ؑ کے تابع تھے، بائیبل میں قول مسیح ہے:
’’یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتاب کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے مسیح کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھلائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو اُن پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا‘‘۔ (انجیل متی ۵: ۱۷، ۱۸، ۱۹)
ایک جانب تو شریعت کی یہ فضیلت و منقبت، دوسری جانب پولس کہتا ہے کہ:
’’پہلا حکم (توریت یا شریعت) کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا‘‘۔ (عبرانیوں ۷: ۱۸)
پادری اسمتھ لکھتے ہیں کہ:
’’یہودی مسیحی (مختون لوگ) یہ سمجھتے تھے کہ مسیحیت درحقیقت یہودیت کی ایک بہتر اور پاک تر شکل ہے۔ عین اس موقع پر انقلاب پسند پولوس وارد ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت صرف ایک محدود وقت کے لیے تھی، اس کا کام محض لوگوں کو مسیح کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا تھا‘‘۔ (حیات و خطوط پولس، مصنفہ پادری جے پیٹرسن اسمتھ، مترجمہ پادری ایس این طالب الدین، مطبوعہ ۱۹۵۲ء ص ۸۲، ۸۳)
ہم قارئین کے لیے پولس کے ان اقوال کو نقل کرتے ہیں جو اس نے شریعت کی ’’شان‘‘ میں کہے:
(۱) ’’جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں‘‘۔ (گلتیوں ۳: ۱۰)
(۲) ’’اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں (شریعت) کی طرف کس طرح پھر رجوع کرتے ہو جن کی دوبارہ غلامی چاہتے ہو‘‘۔ (گلتیوں ۴: ۹)
(۳) ’’مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا‘‘۔ (گلتیوں ۳: ۱۴)
(۴) ’’ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس کے ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں مگر جب ایمان آچکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے‘‘۔ (گلتیوں ۳: ۲۳ و ۲۴)
ختنہ کرانا شریعت کا ایک ناقابل تردید حکم تھا، خود مسیح کا ختنہ ہوا۔ پولس نے بھی اپنے مختون ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ پھر آج کل کے مسیحی ختنہ کے کیوں مخالف ہیں؟ دراصل وہ پولس کی پیروی میں مارے گئے۔ پولس کا فلسفہ ہے کہ
(۵) ’’اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح میں تم کو کچھ فائدہ نہ ہو گا‘‘۔ (گلتیوں ۵: ۲)
(۶) ’’تم جو شریعت کے وسیلہ سے راستباز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم‘‘۔ (گلتیوں ۵: ۴)
(۷) ’’شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راستباز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں‘‘۔ (گلتیوں ۳: ۱۱، ۱۲)
پیغامِ مسیح ؑ تو فقط یہودیوں کے لیے اور شریعتِ موسوی ؑ کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ پولوس کے مذکورہ رویہ سے شاگردانِ مسیح ؑ اور پولوس کی راہیں جدا جدا ہو گئیں، پادری بلیکی لکھتے ہیں:
’’رسولوں کے زمانہ میں مسیحی کلیسیا کی تاریخ، جو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے، ان میں ایک قوم یہود ہے اور دوسری غیر اقوام سے وابستہ ہے۔ یہودی تاریخ کی شاخ دوبارہ رسولوں سے علاقہ رکھتی ہے اور غیر قوموں کی تاریخ زیادہ تر پولوس کی حرکات سے وابستہ ہے۔ کتاب اعمال کا پہلا حصہ پہلی شاخ کا بیان قلمبند کرتا ہے اور باقی ماندہ حصہ دوسری شاخ کا‘‘۔ (تواریخ بائبل، مصنفہ پادری ولیم جی بلیکی ڈی ڈی، مترجمہ پادری طالب الدین، مطبوعہ ۱۹۵۵ء ص ۵۲۵)
اس ضمن میں انجیل برنباس کا بیان حسبِ ذیل ہے:
’’عزیزو! بے شک خدائے عظیم عجیب نے اس پچھلے زمانہ میں اپنے نبی یسوع مسیح کی معرفت ہماری خبر گیری اپنی بڑی مہربانی سے کی۔ ان آیتوں اور اس تعلیم کے بارہ میں جس کو شیطان نے تقوی کے نمائشی دعوے سے بہت سارے آدمیوں کو گمراہ بنانے کا ذریعہ ٹھہرا لیا ہے، وہ سخت کفر کی منادی کرنے والے ہیں۔ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ختنہ کرانے سے انکار کرتے ہیں جس کا خدا نے ہمیشہ حکم دیا ہے۔ ہر نجس گوشت کو جائز بتلاتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کے شمار میں پولس بھی گمراہ ہوا۔ وہ کہ اس کی نسبت جو کچھ کہوں افسوس ہی سے کہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میں اس حق کو لکھ رہا ہوں جیسے کہ میں نے اس اثنا میں دیکھا ہے جب کہ میں یسوع کی رفاقت میں تھا۔ اور یہ اس لیے لکھتا ہوں تاکہ تم چھٹکارا پاؤ اور شیطان تم کو ایسا گمراہ نہ کرے کہ اس گمراہی سے تم خدا کا دین قبول کرنے میں ہلاک ہو جاؤ‘‘۔ (انجیل برناباس، مقدمہ آیت ۲ تا ۷)
اس اقتباس کے سیاق میں (اعمال ۱۵: ۳۶ تا ۴۱) اور (گلتیوں ۲: ۱۱ تا ۱۴) پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ پولس برناباس اور پطرس کے درمیان غیر قوموں کے بارے میں جھگڑا تھا۔ مختصرًا یہ کہ برنباس اور پولس پہلے اکٹھے تبلیغ کے لیے جاتے رہے۔ ان کا ایک ساتھی ’’یوحنا مرقس‘‘ تھا، ایک سفر کے دوران یہ رستے ہی سے واپس آگیا۔ جب دوبارہ سفر کا موقعہ آیا تو لوقا بیان کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے کی وجہ ’’یوحنا مرقس‘‘ تھا۔ برنباس اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا جبکہ پولس کا موقف یہ تھا کہ ہمیں ایک بے وفا شخص کو ساتھ نہ لے جانا چاہیئے۔ اس پر ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے (اعمال ۱۵: ۳۹)۔ اس کے بعد اعمال کی کتاب میں برنباس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ پادری جے پیٹرسن اسمتھ اس واقعہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ وہ اس جھگڑے کے بعد کبھی نہ ملے (ایضًا ص ۹۰)۔
اخلاص اور اس کی برکات
الاستاذ السید سابق
ترجمہ و ترتیب: حافظ مقصود احمد
اخلاص یہ ہے کہ انسان کا قول، عمل اور ہر کوشش صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، اس کے قول و عمل میں طلبِ جاہ و مال یا ریا نہ ہو۔
اسلام میں اخلاص کی اہمیت
قرآن میں متعدد بار اخلاص کی طرف دعوت دی گئی ہے، فرمایا:
وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ (البینہ)
’’اور ان کو یہی حکم ہوا کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کریں۔‘‘
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کا مدار اخلاص ہی کو ٹھہرایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بروایت ابن ابی حاتم، عن طاووس ۔۔۔) ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں حج کرتا ہوں اور مناسک کی ادائیگی کے وقت میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ لوگوں کو میرا ان مناسک کو ادا کرنا معلوم ہو جائے، وہ دیکھیں کہ میں یہ نیک اعمال کر رہا ہوں ۔۔۔ آپؐ نے سن کر کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:
فمن کان یرجوا لقاء ربہ فلیعمل عملًا صالحًا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدًا (الکہف)
’’پھر جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔‘‘
اخلاص کمالِ ایمان کی دلیل ہے
ابوداؤدؒ اور ترمذیؒ نے سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے:
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من احب اللہ و ابغض للہ و اعطٰی للہ و منع للہ فقد اتکمل الایمان۔
’’جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اسی کے لیے دعا اور اسی کی خاطر روکا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔‘‘
اللہ سبحانہ دلوں کو دیکھتے ہیں مظاہر اور اشکال کو نہیں دیکھتے۔ حضرت ابوہریرہؓ نے روایت کی ہے:
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا ینظر الیٰ اجسامکم ولا الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم۔ (مسلم)
’’اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے دلوں (کی نیتوں) کو دیکھتے ہیں۔‘‘
ابو موسٰی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی اپنی بہادری کے اظہار کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی قومی حمیت کے تحت لڑتا ہے، ایک آدمی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون شخص راہِ خدا میں لڑ رہا ہے؟ آپؐ نے فرمایا، جو شخص اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے یعنی جس کا لڑنا کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ (بخاری و مسلم)
عمل کا معیار
کوئی عمل اس وقت تک عمل خیر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس کے کرنے میں نیت نیک نہ ہو اور خالص اللہ کے لیے نہ ہو کیونکہ ہر عمل کی ایک غایت ہوتی ہے اور غایت اولٰی ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سوائے خیر کے کسی کام کا حکم نہیں کرتا اور سوائے خیر کے کسی چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ لہٰذا انسان کی تمام زندگی کا مقصد اپنے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے طلبِ خیر ہونا چاہیئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، وانما لکل امرئٍ ما نوی، فمن کانت ھجرتہ الی اللہ ورسولہ فھجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ھجرتہ الی دنیا یصیبھا او امراۃ ینکحھا، فھجرتہ الی ما ھاجر الیہ۔ (بخاری و مسلم)
’’اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ لہٰذا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کا اسے ثواب ملے گا اور اگر کسی نے کسی دنیاوی غرض کے لیے ہجرت کی تو اسے وہی کچھ ملے گا اور اگر کسی عورت کے لیے ہجرت کی (تو ہو سکتا ہے کہ) اس سے نکاح کر لے لیکن آخرت میں ان کا اجر مرتب نہ ہو گا۔‘‘
اخلاص کی قیمت
اخلاص اور نیک نیت سے انسان کو رفعت و بلندی عطا ہوتی ہے اور اس کو ابرار کی منازل پر لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
طوبٰی للمخلصین: الذین اذا حضروا لم یعرفوا ۔۔۔ اذا غابوا لم یفتقدوا ۔۔۔ اولئک مصابیح الھدی تنجلی عنھم کل فتنۃ ظلماء۔ (رواہ البیہقی عن ثوبانؓ)
’’مخلصین کے لیے بشارت ہو، وہ لوگ کہ جب وہ کسی جگہ موجود ہوں تو کوئی انہیں جانتا نہ ہو، اور جب وہ کسی جگہ موجود نہ ہوں تو ان کی کمی محسوس نہ ہو، یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، انہی کی برکت سے انسان پر آئی ہوئی مصیبت ٹلتی ہے۔‘‘
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے لوگوں کا واقعہ ہے کہ تین آدمی سفر کے لیے نکلے، دورانِ سفر ایک غار میں پناہ کے لیے ٹھہر گئے، اچانک غار کے دہانے پر ایک بڑا پتھر گرا اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا (پتھر اتنا بڑا تھا کہ ان کے زور لگانے کے باوجود نہ ہلا) پھرآپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ پتھر خدا ہی ہٹائے تو ہٹے گا، لہٰذا اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اس سے دعا کریں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ! میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں کھانے پینے کی ہر چیز پہلے انہیں دیتا اور بعد میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے بہت دور نکل گیا، واپس لوٹا تو وہ سو چکے تھے، میں نے ان کے لیے دودھ دوہا اور لے کر ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، انہیں جگانا میں نے مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے اپنے بچوں کو دینا بھی مجھے گوارا نہ ہوا حالانکہ وہ میرے قدموں میں بھوک کے مارے بلبلاتے ہوئے سو گئے۔ پیالہ ہاتھ میں پکڑے میں اسی طرح کھڑا رہا اور میرے ماں باپ سوتے رہے حتٰی کہ صبح ہو گئی اور وہ ازخود اٹھے اور دودھ پیا ۔۔۔۔ یا اللہ! اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ (قدرت خداوندی سے) پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن نکلنے کی جگہ نہ بن سکی۔
دوسرا بولا، یا اللہ! میری ایک چچازاد بہن تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی (ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا جیسی ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے) میں نے اسے اپنے ڈھب پر لانا چاہا لیکن وہ ہر بار میری بات ٹال دیتی یہاں تک کہ اس پر قحط کی نوبت آ گئی۔ میں نے اسے ایک سو بیس دینار دیے اس شرط پر کہ وہ میری حاجت پوری کرے گی۔ وہ (بیچاری بامر مجبوری) میری بات مان گئی۔ یہاں تک کہ جب میں اس پر پوری طرح قادر ہو گیا تو کہنے لگی (اے اللہ کے بندے) خدا سے ڈر اور جس مہر کو اللہ تعالیٰ نے لگایا اس کو ناحق نہ توڑو (عقد شرعی کے بغیر ایسا مت کرو) میں فورًا اس سے علیحدہ ہو گیا حالانکہ وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھی اور جو سونا (بصورت دینار) اسے دیا تھا وہ بھی اسی کے پاس رہنے دیا۔ یا اللہ! اگر میرا یہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔
تیسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدور کام پر لگائے، سب کو میں نے مزدوری دے دی سوائے ایک مزدور کے جو مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے اس کی رقم کاروبار پر لگا دی جس سے بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو گیا، وہ کچھ عرصے کے بعد آیا اور اپنی مزدوری طلب کی۔ میں نے تمام اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں اس کے سامنے کر دیں اور کہا کہ یہ سب تمہارے ہیں۔ اتنا مال دیکھ کر وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے! میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں نے کہا کہ یہ مذاق نہیں (بلکہ سب مال تمہارا ہے اور ساتھ ہی تمام ماجرا سنایا کہ میں نے تمہارا مال تجارت پر لگایا اور اس طرح یہ مال بڑھ گیا)۔ اس نے مال لیا اور چلا گیا اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ یا اللہ! اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ (خوش خوش) نکل کر چلے گئے۔ (بخاری و مسلم)
جو شخص صفت اخلاص سے متصف ہو گا اسے کامیابی حاصل ہو گی۔ جس جماعت میں ایسے افراد ہوں گے اس جماعت میں خیر و برکات کا دور دورہ ہو گا، گھٹیا صفات اس میں معدوم ہوں گی۔ دنیاوی شہوات ان سے مرتفع ہوں گی۔ ملت میں اعلیٰ مقاصد کا حصول ان کا مطمع نظر ہو گا اور معاشرے میں امن و سلامتی عام ہو گی۔
یہ اخلاص ہی کی برکت تھی کہ صحابہؓ میں ریا، نفاق اور جھوٹ بالکل معدوم تھا۔ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کا حصول ہی ان کا مقصدِ حیات تھا۔ تمام صحابہؓ اقامتِ دین، اعلاء کلمۃ اللہ، عدل و انصاف کو عام کرنے اور رضائے خداوندی کو اصل مقصود سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت و شوکت عطا فرمائی، دنیا کا مقتدا بنایا اور وہ تمام عالم کے سردار بن گئے۔
عمل میں اگر کچھ کمی بشری کمزوری کی وجہ سے رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے اس عمل کا پورا پورا اجر فرما دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے غزوۂ تبوک میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپؐ نے فرمایا (ہم تو یہاں جہاد کر رہے ہیں لیکن) مدینہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی سفر نہیں کیا کوئی وادی طے نہیں کی مگر (ثواب میں) وہ تمہارے ساتھ ہیں، انہیں مرض نے گھیر لیا (ورنہ نیت ان کی بھی جہاد کی تھی) ۔ اور ایک روایت میں ہے ’’مگر ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں‘‘ (ابوداؤد اور ترمذی)۔
حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیند کے غلبہ کی وجہ سے سحری کو اٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے اسے اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب دیتے ہیں اور نیند پر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔
سہل بن حنیفؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:
من سأل اللہ الشھادۃ بصدق، بلغہ اللہ منازل الشھداء وان مات علی فراشہ۔
’’جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگے تو اللہ اسے شہداء کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔‘‘
ریا اور بری نیت
جس طرح صفت اخلاص اور نیک نیت سے متصف ہونے سے انسان کو اعلیٰ مرتبہ نصیب ہوتا ہے اسی طرح سے ریاء سے متصف ہونے سے اور بری نیت کی وجہ سے انسان اسفل سافلین کے درجے میں جا گرتا ہے کیونکہ عمل کا اصل باعث اخلاقی عنصر ہے اور وہی رب تعالیٰ سبحانہ کی نظر کا محور ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اسی اخلاقی عنصر کو دیکھتے ہیں، عمل کا درجہ ثانوی ہے) جیسے ایک حدیث ہے کہ حضرت ابوبکرۃؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں سونت کر آمنے سامنے آتے ہیں (اور نتیجے میں ایک قتل ہو جاتا ہے) تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قاتل کا دوزخی ہونا تو سمجھ میں آ گیا لیکن مقتول کیونکر دوزخی ہوا؟ آپؐ نے فرمایا، مقتول بھی تو اپنے مدمقابل کو قتل کرنے پر حریص تھا۔ (بخاری و مسلم)
غرضیکہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ بھی اسے دوزخ میں لے گیا۔ اللہ سبحانہ حساب تو نیتوں پر لیں گے خواہ وہ ظاہر کرے یا اسے چھپائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:
وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ (بقرہ ۲۸۴)
’’خواہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو اللہ تعالیٰ تم سے حساب ضرور لیں گے۔‘‘
اسی فرمان باری تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سے واضح فرمایا:
ان اللہ تعالیٰ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک۔ فمن ھم بحسنۃ فلم یعلمھا کتبھا اللہ عندہ حسنۃ کاملہ۔ وان ھم بھا فعملھاکتبھا اللہ عشر حسنات الی سبع مائۃ ضعف الی اضعاف کثیرہ۔ وان ھم بسیئۃفلم یعملھا کتبھا اللہ حسنۃ کاملۃ۔ وان ھم بھا فعملھا کتبھا اللہ سیئۃ واحدۃ۔ (رواہ البخاری و مسلم عن عبد اللہ بن عباس)
’’اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور بدیوں کو لکھا اور ہر ایک کو واضح کر دیا۔ پھر جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس نیکی پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے وہ نیکی بھی کر گزرے تو اسے ایک نیکی کے بدلے دس سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں (یعنی اخلاص میں جتنی قوت ہو گی اتنا ہی اجر زیادہ ہو گا)۔ لیکن اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ برائی نہیں کی تو اس (اجتناب) پر بھی ایک کامل نیکی اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور اگر بدی کا ارادہ کر کے وہ گناہ بھی کر لیا تو صرف ایک گناہ ہی لکھا جائے گا۔‘‘
یعنی اگر برائی کا ارادہ کر کے خوفِ خدا اور اس پر ایمان کی وجہ سے برائی سے باز رہا تو عند اللہ یہ ایک نیکی گنی جائے گی، لیکن اگر وہ گناہ کسی خارجی سبب سے نہ کر سکا تو یہ کوئی نیکی نہیں لیکن اس پر بھی اسے خدا کا شکر کرنا چاہیئے کہ اس نے گناہ سے بچا لیا۔ مزید براں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ان اللہ تجاوز عن امتی عما حدثت بہ انفسھا۔
’’اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں کے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے۔‘‘
ریا کی شان (اثر) یہ ہے کہ وہ بندے اور خدا کے درمیان حجاب بن جاتی ہے اور اسے حیوانوں کے زمرے میں لا شامل کرتی ہے، پھر اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو پاتا۔ اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا کیونکہ دکھلاوے کے کام کرنے والے کی نہ کوئی رائے ہوتی ہے نہ اس کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے بلکہ وہ ’’گرگٹ‘‘ کی طرح ہوتا ہے کہ رنگ بدلتا رہتا ہے اور ہوا کے رخ پر چلتا ہے، عمل کی پختگی اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ ریا کا مطلب ہے عبادات کے ذریعے جاہ و منزلت کا طلب کرنا اور اللہ سبحانہ نے اس سے بچنے اور اسے ترک کرنے کا صریحًا حکم فرمایا ہے کیونکہ اس سے انفرادی اور اجتماعی برائیاں پھیلتی ہیں، اس لیے فرمایا:
والذین یمکرون السیئات لھم عذاب شدید و مکر اولئک ھو یبور (فاطر ۱۰)
’’اور جو لوگ برائیوں کے داؤ میں ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ ہے ٹوٹے کا۔‘‘
اور جو لوگ برائی کے مکر کرتے ہیں یہی اہل الریاء ہیں اور ریاء منافقین کی صفت ہے جن کا مبداء و معاد پر ایمان نہیں اور نہ ہی وہ صالح عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے:
ان المنافقین یخادعون اللہ وھو خادعھم واذا قاموا الی الصلوٰۃ قاموا کسالیٰ یراءون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلًا۔ (نساء ۱۴۲)
’’البتہ منافقین دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے بددلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔‘‘
اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس دھوکہ دہی کا پردہ فاش کر دے گا اور یہ چھپانا اس آدمی کے لیے باعث ذلت و رسوائی بنے گا اور دکھلاوے کے لیے دھوکا دینے والے کی جگ ہنسائی ہو گی اور یہی اس کے دکھلاوے کی سزا ہو گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ’’من سمع سمع اللہ و من یائی یرائی اللہ بہ‘‘۔جس نے دکھلاوے کے لیے کام کیا اللہ تعالیٰ یہ کام اس کے لیے باعث رسوائی بنا دے گا اور جس نے کوئی نیک کام اس نیت سے کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو تو وہ اس کی عزت کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب فرما دیں گے کہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ اس کی اصل نیت کیا تھی۔
اور ریا شرک ہی کی ایک قسم ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ محمود بن لبیدؓ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، ریاء۔ جب قیامت کے روز لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ (دکھلاوے کے لیے کام کرنے والوں کو) فرمائے گا جن لوگوں کو تم دنیا میں دکھا کر کام کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، ذرا دیکھو تو تمہیں ان کے ہاں سے کوئی بدلہ ملتا ہے!
اسلام انسان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہو۔ اس کے رات کی سیاہی دن کی روشنی کی طرح ہو۔ جب ظاہر و باطن میں اختلاف ہو، قول اور فعل میں مطابقت نہ رہے، اور انسان خیر کی بجائے شر کو ترجیح دینے لگے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی نفاق کی مرض میں مبتلا ہے۔ اب اس کے اندر حق کی علی الاعلان حمایت کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے۔ جرأت و حوصلہ جو ایک مومن صادق کا طرۂ امتیاز ہے یہ اس سے یکسر محروم ہو جاتا ہے۔ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں روایت کی ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ جب ہم بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم آپس میں نہیں کرتے۔ سن کر انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں ہم اسی رویے کو نفاق سمجھتے تھے۔
بعض لوگ دکھلاوے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کا خوب چرچا ہوتا ہے لیکن ان کا کام چونکہ خلوص پر مبنی نہیں ہوتا اس لیے اس پر نیک اثر بھی مرتب نہیں ہوتا۔ امام مسلمؒ نے حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ ہو گا وہ شہید ہو گا۔ اسے دربارِ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا پھر سے سوال ہو گا: تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ جواب دے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جنگ اس لیے لڑی کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا بہادر تھا۔ چنانچہ لوگوں نے تیری تعریف کر دی (اب ہمارے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں)۔ پھر اس کے متعلق فیصلہ صادر ہو گا اور وہ منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا، اس نے علم سیکھا اور سکھایا ہو گا اور قرآن کا قاری ہو گا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ پھر سوال ہو گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تو نے تو اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، پس یہ کچھ کہا گیا اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور یہ بھی کہا گیا (اب ہمارے پاس اس کا کچھ اجر نہیں) پھر اس کو حسب الحکم منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا، اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت عطا فرمائی ہو گی۔ ہر قسم کا مال و دولت اسے میسر تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان کا اعتراف بھی کرے گا، پھر سوال ہو گا، ان نعمتوں کے بدلے میں دنیا میں تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، میں نے تیری رضا کے لیے ہر نیک کام کیا اور ان کاموں میں مال خرچ کیا۔ ارشاد ہو گا، تو جھوٹا ہے۔ تو نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، پس یہ کچھ کہا گیا (اب تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں) پھر اسے حسب الحکم منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیا جائے گا (اعاذنا اللہ منھا)۔
حدیثِ مذکورہ سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اگر لوگ تعریف کریں گے تو عمل اکارت جائے گا بلکہ اگر کوئی کام نیک نیت اور اخلاص سے کیا جائے اور لوگوں کو اس کا علم ہو گا اور انہوں نے اس کی تعریف کی (اور اس تعریف پر اس کا اپنا مقصد نہیں تھا) تو اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا خواہ ان کی یہ تعریف اسے بھلی ہی معلوم کیوں نہ ہو۔
ترمذیً نے ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے، ایک شخص نے کہا ، یا رسول اللہ! ایک شخص لوگوں سے چھپا کر کوئی عمل کرتا ہے لیکن لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے، اب وہ شخص اس بات پر خوش ہوتا ہے (تو کیا اس عمل کا اسے ثواب ملے گا؟) آپؐ نے فرمایا اسے دو ثواب ملیں گے، ایک تو چھپانے کا ثواب اور ایک ظاہر ہونے کا ثواب ’’لہ اجران، اجر السر و اجر العلانیۃ‘‘۔ بلکہ لوگوں کی یہ تعریف ایک قسم کی بشارت ہے جو دنیا میں اسے مل گئی۔ ’’کما قال صلی اللہ علیہ وسلم انتم شہداء اللہ علی الارض‘‘۔
امام مسلمؒ نے حضرت ابوذرؓ سے روایت کی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایک شخص نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا، یہ مومن کے لیے دنیا میں ہی بشارت ہے۔
ریاء سے خوف
حضرت ابو موسٰی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! اس شرک سے ڈرو کیونکہ یہ چیونٹی کے قدموں کی آہٹ سے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہا کرو ’’اللھم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئًا نعلمہ، ونستغفرک لما لا نعلمہ‘‘۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاء سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کی نعمت سے نوازے، آمین۔
چاہِ یوسفؑ کی صدا
پروفیسر حافظ نذر احمد
آ رہی ہے چاہِ یوسفؑ سے صدا
دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت
ارضِ مقدس (فلسطین) کا یہ کنواں ’’چاہِ یوسفؑ‘‘ اور ’’چاہِ کنعان‘‘ دو ناموں سے مشہور ہے۔ یہ تاریخی کنواں کبھی کا خشک ہو چکا ہے۔ توریت مقدس کا بیان ہے کہ جب ننھے یوسفؑ کو کنویں میں گرایا گیا اس میں پانی نہ تھا لیکن اس کنویں کی عظمت اس کے پانی سے نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک گونہ نسبت کے سبب سے ہے۔ چاہِ یوسفؑؑ کے محل و وقوع اور حالات و کوائف کے مطالعہ سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کا مطالعہ کر لیا جائے۔ چونکہ یہ کنواں انہی کی نسبت سے مشہور ہوا، ورنہ کنویں میں اور کوئی ایسی انفرادی خصوصیت نہیں جو اس کی شہرت کا باعث ہوتی۔
حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبیؑ کے بیٹے تھے، نبیؑ کے پوتے اور نبیؑ کے پڑپوتے تھے۔ ان کے والد ماجد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، دادا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پڑدادا کا اسمِ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ یہ خاندان ہی انبیاءؑ کا خاندان تھا۔ اس خاندان میں حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت موسٰیؑ اور حضرت عیسٰیؑ جیسے جلیل القدر نبی ہوئے ہیں، ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے گرامیٔ قدر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ’’اسرائیل‘‘ تھا۔ یہ عربانی لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ ان کے اسی لقب کی نسبت سے ان کی اولاد کو ’’بنی اسرائیل‘‘ کہا جاتا ہے یعنی اولادِ یعقوب ؑ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ قبل مسیح ؑ متعین کیا گیا ہے۔ وطن جدون تھا۔ اس قصبہ کا دوسرا نام ’’الخلیل‘‘ ہے، کیوں نہ ہو ’’خلیل اللہ‘‘ کی اولاد کی نگری ہے۔ یہ بستی ارضِ مقدس کے مشہور شہر بیت المقدس کے قریب ہی واقع ہے۔ چار ہزار سال پرانی یہ بستی آج موجود ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیاری عادات، موہنی صورت اور عمر میں سب سے چھوٹے ہونے کے سبب سب کے منظورِ نظر تھے۔ خصوصًا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بچہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت یوسفؑؑ کے بھائی ان سے جلنے لگے۔ یوں بھی بن یامین کے سوا ان کا کوئی حقیقی بھائی نہ تھا اور سوتیلے بہن بھائی اکثر رقابت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، پھر حضرت یوسفؑؑ کے خوابوں نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے ننھی عمر ہی میں کچھ خواب دیکھے جو اُن کے روشن مستقبل کا پتہ دے رہے تھے۔ ان کی تعبیر سے سوتیلے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ اور بھڑکی۔
برادرانِ یوسفؑؑ کی سازش
یوسف علیہ السلام جیسے معصوم پیارے بھائی کے خلاف ان لوگوں نے ایک خوفناک سازش کی، سب مل کر باپ کے پاس گئے اور یوسفؑؑ کو جنگل ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ کہنے لگے ہم بھیڑ بکریاں چرائیں گے، شکار کریں گے، یوسفؑؑ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، خوب تفریح رہے گی۔ حضرت یعقوبؑ کی دوربین نگاہیں گویا آنے والے حادثات کو دیکھ رہی تھیں، انہوں نے برادرانِ یوسفؑؑ کی درخواست قبول کرنے میں پس و پیش کیا لیکن بیٹوں کے مسلسل اصرار اور حفاظت کے پختہ وعدوں پر بادلِ نخواستہ راضی ہو گئے اور یوسفؑؑ کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔
گھر سے نکل کر یہ لوگ دریائے اردن کے کنارے پہنچے۔ جنگل میں ’’دوتین‘‘ شہر کے قریب انہوں نے حضرت یوسفؑؑ کے قتل کا منصوبہ بنانا چاہا، روبن نے سخت مخالفت کی، اس نے مشورہ دیا کہ یوسفؑؑ کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں اور اس کا خون اپنے ذمہ نہ لیں بلکہ کنویں میں دھکا دے دیں، ہو سکتا ہے کوئی راہ چلتا مسافر نکال کر یہاں سے دور لے جائے، اس طرح یہ کانٹا راستہ سے ہٹ جائے گا اور اس کا خون بھی سر نہ چڑھے گا۔ روبن کی تجویز ان کی سمجھ میں آگئی، پہلے انہوں ’’بوقلمونی قبا‘‘ یوسفؑؑ کے جسم سے زبردستی، پھر کنویں میں دھکا دے دیا۔ یہ قبا حضرت یعقوبؑ نے خاص طور پر ان کے لیے تیار کروائی تھی۔ یوسفؑؑ کو کنویں میں گرا کر وہ اپنی جگہ بالکل مطمئن ہو گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آج جسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھ رہے ہیں کل وہی ان کا محسن ہو گا اور پورے خاندان کو فقر و فاقہ سے نجات دلائے گا۔
چاہِ یوسفؑؑ کی تحقیق
قرآن مجید میں اس کنویں کا ذکر موجود ہے۔ عربی زبان میں کنویں کو ’’بیئر‘‘ اور ’’جُب‘‘ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کنویں کے لیے لفظ ’’جُب‘‘ ہی آیا ہے، ارشاد ہے:
قال قائل منھم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب۔
’’ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسفؑؑ کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کنویں میں گرا دو۔ (سورہ یوسف ۱۰)
لفظ جُب کے دو معنی ہیں (۱) جڑ سے کاٹ دینا (۲) کنواں۔ یہاں یہ لفظ اپنے دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دراصل جُب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر اینٹوں وغیرہ سے باقاعدہ نہ بنائی گئی ہو اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہو۔ جس کنویں کی منڈیر اور دیواریں ہوں اسے عربی میں ’’بئیر‘‘ کہتے ہیں۔ (مفردات القرآن، راغب)
اس کنویں کا محل وقوع جاننے کے لیے ذرا اس کے گرد و پیش پر نظر ڈال لیجئے۔ بیت المقدس فلسطین کا مرکزی شہر ہے۔ ارضِ مقدس کے اس شہر سے کوئی پچیس میل کے فاصلے پر دریائے اردن بہتا ہے۔ یہ دریا اس قدر اہم ہے کہ اس کی نسبت سے پورے ملک کا نام ہی شرقِ اردن پڑ گیا۔ یہی وہ دریا ہے جس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اصطباغ (بپتسمہ) لیا تھا۔ دریائے اردن کے کنارے طبریہ سے دمشق کو جاتے ہوئے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر چاہِ یوسفؑؑ کا مقام آتا ہے۔ طبریہ فلسطین کا ایک تاریخی شہر ہے اور دمشق ملک شام کا دارالخلافہ ہے۔ طبریہ کے دوسری سمت فلسطین کی ایک دوسری قدیم ترین بستی ناصریہ واقع ہے اسے انگریزی میں Nazarath نزرات کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی نسبت سے انہیں ’’مسیحِ ناصری‘‘ کہتے ہیں اور ان کے ماننے والے عیسائی اور مسیحی کے علاوہ ’’نصرانی‘‘ اور ’’نصارٰی‘‘ بھی کہلاتے ہیں۔
یہ کنواں آبادی سے دور جنگل بیابان میں تھا جیسا کہ بائبل کے اس بیان سے واضح ہے:
’’اور ان سے کہا خونریزی نہ کرو لیکن اسے کنویں ڈال دو جو بیابان میں ہے‘‘۔ کتاب پیدائش ۳۷: ۱۹، ۲۰)
اسی کتاب پیدائش کے باب ۳۷ کی آیت ۲۴ کا بیان ہے:
’’اسے پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنواں سوکھا تھا، اس میں پانی کی بوند نہ تھی۔‘‘
ہمارے اکثر مفسرین کرام نے اس بیان سے اختلاف کیا ہے۔ چاہِ یوسفؑؑ کا تذکرہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنی سیاحت کے دوران اس کنویں کی زیارت کی تھی۔ ابن بطوطہ کے بیان کے مطابق یہ کنواں ایک رہگزر پر تھا اور اگلے وقتوں میں کنویں عام طور پر راستوں پر ہی بنائے جاتے تھے تاکہ مسافروں کو پانی کی سہولت رہے۔ چنانچہ قافلے عام طور پر کارواں سراؤں کے علاوہ کنویں پر ہی پڑاؤ ڈالتے تھے۔
مشہور مفسر امام النسفی نے اپنی کتاب ’’مدارک التنزیل‘‘ میں لکھا ہے کہ یہ کنواں حضرت یعقوبؑ کے گھر سے تین فرسخ یعنی تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر تھا اور اس وقت کنویں میں پانی موجود تھا۔ چنانچہ بھائیوں نے جب حضرت یوسفؑؑ کو کنویں میں گرایا تو انہوں نے مینڈھ پر پناہ لی اور کنویں میں سیدھے کھڑے ہو گئے۔
حضرت یوسفؑؑ کنویں میں
جب بھائی یوسفؑؑ کو جنگل ساتھ لے کر چلے تھے انہوں نے باپ سے حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں لیکن نیت بد تھی اور ان کے وعدوں کی حیثیت ایک فریب سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ وہ حضرت یوسفؑؑ کو کھیل کود اور شکار کے بہانے ’’دوتین‘‘ کے جنگل میں لے آئے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، انہوں نے یہاں پہنچ کر قتل کر ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا، خدا بھلا کرے روبن کا کہ اس نے انہیں اس ارادہ سے روکا، اس کے سمجھانے پر انہوں نے کنویں میں گرا دینے کا فیصلہ کیا جیسا کہ ہم ابتداء میں کہہ چکے ہیں، پہلے انہوں نے حضرت یوسفؑؑ کی بوقلمونی قبا اتاری پھر اس سے باندھ کر کنویں میں دھکا دے دیا۔
حضرت یوسفؑؑ کی عمر کا یہ ابتدائی حصہ تھا۔ بائبل کی روایت کے مطابق اس وقت ان کا سن سترہ برس کا تھا (ملاحظہ ہو ’’توراۃ مقدس‘‘ کتاب پیدائش باب ۳۷ آیت ۳)۔ معلوم نہیں معصوم اور بے گناہ یوسفؑؑ کے دل پر اس وقت کیا گزری ہو گی؟ اور ان کے من میں کیا کیا خیال آئے ہوں گے؟ عین اس مایوسی اور غم کے عالم میں اللہ پاک نے انہیں تسلی دی جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے:
’’ہم نے یوسفؑؑ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہم ان بھائیوں کو یہ بات جتلائیں گے اس وقت ان کو پتہ بھی نہ ہو گا‘‘۔ (سورہ یوسف ۱۵)
چاہِ یوسفؑؑ پر قافلہ کا گزر
حضرت یوسفؑؑ کو کنویں سے نکالنے والا قافلہ کن لوگوں کا تھا؟ یہ مسافر کہاں سے آرہے تھے اور کدھر جا رہے تھے؟ یہ تمام سوال جواب طلب ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت قافلہ کی آمد کو محض حسن اتفاق سمجھا جائے۔ نہیں، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ قافلہ کو یہاں پہنچا کر یوسفؑؑ نبی کو بچانا مقصود تھا اور آگے چل کر ان کے ذریعے کئی قوموں کی تقدیر بدلنی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنی قدرتِ کاملہ سے ایسے ’’حسنِ اتفاق‘‘ ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ اس سلسلہ میں بائبل کا بیان ہے کہ جب بھائیوں نے ایک قافلہ اس طرف آتے دیکھا تو یوسفؑؑ کو فروخت کرنے کی سازش کی اور آپس میں یوں کہنے لگے:
’’آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور خون ہے (سبحان اللہ کس برادرانہ شفقت کا مظاہرہ ہے) اس کے بھائیوں نے اس کی بات نہ مانی۔ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسفؑؑ کو گڑھے سے کھینچ کر باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھوں بیس روپیہ میں فروخت کر ڈالا اور وہ قافلے والے یوسف کو مصر لے گئے۔ جب روبن گڑھے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ یوسفؑؑ گڑھے میں نہیں ہے تو اس نے اپنا پیرہن چاک کر ڈالا‘‘۔ (کتاب پیدائش ۴۷: ۲۷ تا ۲۹)
بائبل کے مندرجہ بالا حوالے میں جن لوگوں کو ’’مدیانی سوداگر‘‘ کہا گیا ہے ان سے حجاز (عرب) کے اسماعیلی عرب مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ عبرانی زبان میں اسماعیلیوں کو مدیانی کہتے تھے۔ بعض اصحاب ’’مدیانی‘‘ کو ’’مدین‘‘ سے منسوب کرتے ہیں یعنی وہ علاقہ جو سعیر سے بحر احمر تک اور شام سے یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ مدین کا علاقہ حجاز کہلاتا ہے (ملاحظہ ہو ’’ارض القرآن‘‘ ج ۲ ص ۴۷ تا ۴۹)۔ مختصر یہ کہ عرب تاجروں کا ایک قافلہ یمن کے دارالخلافہ صفا شہر سے مصر جا رہا تھا، قافلہ کے اونٹوں پر گرم مصالحہ اور ملبان وغیرہ لدا ہوا تھا، قافلہ والوں کی نظر جب خوبرو اور خوش اطوار یوسفؑؑ پر پڑی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کلام پاک میں آتا ہے کہ وہ بے ساختہ پکار اٹھے ’’یا بشرٰی ھذا غلام‘‘ ارے واہ واہ! یہ تو ایک لڑکا نکل آیا‘‘۔ (سورہ یوسف ۱۲: ۱۹)
حضرت یوسفؑؑ کنویں سے باہر
قافلے والے ننھے یوسفؑؑ کو یہاں سے مصر لے گئے اور منہ مانگی قیمت وصول کر لی۔ ان کا خوش قسمت خریدار مصر کا باوقار حکمران تھا، اسے فرعون کے دربار میں بڑا مقام حاصل تھا۔ قرآن مجید میں اسے ’’عزیز مصر‘‘ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے اور توراۃ مقدس میں اس کا نام فوطیفار بیان ہوا ہے، لکھا ہے:
’’مدیانیوں نے اسے مصر میں فوطیفار کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ فرعون کا ایک امیر اور لشکر کمانڈر تھا‘‘۔ (کتاب پیدائش ۳۷: ۳۹)
یوسف کا خریدار عزیزِ مصر لاولد تھا۔ میاں بیوی دونوں کو بچہ کی بے حد خواہش تھی مگر ان کا یہ ارمان پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اس حسین و جمیل بچہ سے ان کے گھر میں بہار آ گئی۔ عزیزِ مصر (فوطیفار) کی بیوی کا نام نہ قرآن مجید میں مذکور ہے نہ توراۃ میں۔ البتہ اسرائیلی روایات میں وہ زلیخا کے نام سے مشہور ہے۔ یوسفؑؑ اس کے گھر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ زلیخا کو ان سے محبت ہو گئی، اس نے انہیں اپنے دامِ محبت میں پھنسانا چاہا مگر وہ اس کے دامِ تزویر میں نہ آئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی کوئی بات انہیں اس طرف مائل نہیں کرتی تو اس نے کمرے کے دروازے بند کر لیے مگر پاکباز یوسفؑؑ پر اس کا یہ آخری داؤ بھی کارگر نہ ہوا، اللہ کریم نے ان کی حفاظت کی اور صاف بچا لیا۔
کنویں سے جیل کی کوٹھڑی تک
حضرت یوسفؑؑ کنویں سے ضرور نکل آئے تھے مگر قید و بند کی مزید سختیاں ابھی ان کے مقدر میں لکھی تھیں۔ ان کی پریشانیوں اور آزمائشوں کا دور ابھی باقی تھا۔ چنانچہ جب زلیخا اپنی کسی تدبیر کے ذریعے انہیں گناہ میں ملوث نہ کر سکی تو اس نے الٹا ان پر دست درازی کا الزام لگا دیا اور دھاندلی سے حضرت یوسفؑؑ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ حضرت یوسفؑؑ پورے صبر و شکر کے ساتھ ایامِ اسیری بسر کرتے رہے، ان کی پُراثر شخصیت سے قیدی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ان سے خوابوں کی تعبیریں پوچھتے اور حق و صداقت کا پیغام سنتے۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، کوئی درباری اس کی تعبیر نہ بتلا سکا، جیل کے آزاد شدہ ایک قیدی کو حضرت یوسفؑؑ کی یاد آ گئی۔ وہ ان کی بتلائی ہوئی کتنی ہی تعبیروں کی صداقت آزما چکا تھا، اس شخص نے بادشاہ کو یوسفؑؑ کا پتہ دیا۔
شاہی فرمان جاری ہوا کہ یوسفؑؑ کو رہا کر کے شاہی دربار میں بلایا جائے مگر انہوں نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا جب تک الزام سے بریت کا اعلان نہ ہو، رہائی کا کیا مطلب؟ لیکن الزام کی بنیاد ہی کیا تھی جس کی تحقیق کی جاتی۔ وہ تو محض دھاندلی تھی یا زیادہ سے زیادہ ملک کی ’’خاتون اول‘‘ کی عزت کو بچانے اور اس کی بات کو بالا رکھنے کی تدبیر تھی۔ بہرصورت حضرت یوسفؑؑ کی پاکدامنی اور پاکبازی کا اعلان کر دیا گیا اور وہ باعزت جیل سے باہر آگئے۔ اب یوسفؑؑ دربار کے ایک رکنِ رکین تھے۔ شاہی خزانے کی کنجیاں ان کی تحویل میں تھیں اور پورے ملک کی معاشی پالیسی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ملک میں قحط پڑا تو غلہ کی فروخت اور تقسیم بھی انہی کے سپرد ہوئی۔
کنویں میں ڈالنے والے
کنعان میں قحط سے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لوگ فاقوں کے باعث بھوکے مر رہے تھے، مصری غلہ ان سب کی امیدوں کا سہارا تھا، یوسفؑؑ کو کنویں میں ڈالنے والے ’’برادرانِ یوسفؑؑ‘‘ بھی اس غلہ کی شہرت سن کر غلہ حاصل کرنے کے لیے چل پڑے۔ آج کا بھائی (جسے اپنے خیال میں) وہ ختم کر چکے تھے خزانوں کا مالک تھا اور نادانستہ اس کے سامنے سوالی بن کر آئے تھے۔ اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود وہ حضرت یوسفؑؑ کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسفؑؑ نے انہیں پہچان لیا مگر حقیقی بھائی کو درمیان میں نہ پایا۔ یوسفؑؑ نے اپنے دشمنِ جان بھائیوں کو خوب خوب غلہ دیا اور ہدایت کی اگر کوئی اور بھائی گھر ہے تو آئندہ اسے بھی ساتھ لانا اور زیادہ غلہ ملے گا۔
یہ لوگ گھر لوٹے، باپ کو سارا ماجرا سنایا، جو نوازشات ہوئی تھیں انہیں بڑھ چڑھ کر بیان کیا اور چھوٹے بھائی بن یامین کو ساتھ بھیجنے کی درخواست کی، اس کی حفاظت کے پختہ وعدے کیے، حضرت یعقوبؑ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے چونکہ بن یامین کے بھائی یوسفؑؑ کے بارہ میں بھی یہ لوگ ایسے ہی وعدے کر چکے تھے اور پھر کنویں میں گرا کر بہانہ بنایا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن قحط کے حالات نے اور کچھ ان کے اصرار نے مجبور کر دیا اور حضرت یعقوبؑ نے اجازت دے دی، اس طرح سب گیارہ کے گیارہ بھائی مصر کو چل دیے۔
حضرت یوسفؑؑ نے پہلے سے زیادہ نوازشات کیں اور خوب غلہ دیا مگر ملازمین کو ہدایت کر دی کہ بن یامین کے بورے میں چپکے سے غلے کا پیمانہ چھپا دیں، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ لوگ چلنے لگے تو منادی ہو گئی کہ سرکاری پیمانہ گم ہو گیا ہے جس کسی کے پاس پیمانہ ہو وہ واپس کر دے۔ ان سب نے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم چور نہیں ہیں کہ ایسا کرتے اور اگر ہم میں سے کسی سے پیمانہ برآمد ہو تو اسے قانون کے مطابق غلام بنا لیا جائے۔ تلاشی لی گئی اور بن یامین کے بورے سے پیمانہ برآمد ہو گیا۔ حضرت یوسفؑؑ نے قانون اور فیصلہ کے مطابق بن یامین کو روک لیا، اس طرح بھائی سے بھائی مل گیا۔ برادرانِ یوسفؑؑ بن یامین کے بغیر روتے دھوتے گھر کو لوٹے، باپ کی دنیا پہلے ہی سونی تھی، بن یامین کو نہ پا کر ان کے دل کی نگری بالکل ہی اجڑ گئی۔ انہوں نے بیٹوں کو دوبارہ مصر بھیجا، یہ لوگ حاضر ہوئے تو اس مرتبہ حضرت یوسفؑؑ نے راز سے پردہ اٹھایا، بولے، کچھ یاد ہے تم نے اس کے بھائی یوسفؑؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ حضرت یوسفؑؑ کے ان لفظوں نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ جس بھائی کو وہ کنویں میں گرا کر دل سے بھلا چکے تھے وہ آج ان کے سامنے تختِ حکومت پر جلوہ افروز تھا اور بڑے اختیارات کا مالک تھا۔ اسے پہچان کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے مگر حضرت یوسفؑؑ نے بڑے اطمینان سے فرمایا:
’’نہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے‘‘۔ (سورہ یوسف ۲۹)
ایک تمثیل
حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتی ہے۔ دونوں کی داستانِ حیات کا آغاز مصائب سے ہوتا ہے، اپنوں کے ہاتھوں مصائب، قید و بند، جلاوطنی اور ہجرت دونوں کے ہاں مشترک ہیں۔ کامیابی اور عروج کا انداز بھی ایک جیسا ہے اور آخر دونوں کے دشمن دست بستہ حاضر ہوتے ہیں اور ’’لاتثریب علیکم الیوم‘‘ (سورہ یوسف ۹۲) کا مزدۂ جانفزا سنتے ہیں۔ غالباً اسی لیے حضرت یوسفؑؑ کی داستانِ حیات کو قرآن مجید میں ’’احسن القصص‘‘ کہا گیا ہے ؎
قید میں یعقوب ؑ نے لی گو نہ یوسف کی خبر
لیکن آنکھیں روزنِ دیوارِ زنداں ہو گئیں
شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ
فقہ حنفی کے مستند شارح
ڈاکٹر حافظ محمد شریف
نام
ابوبکر محمد بن ابی سہل احمد، نہ کہ احمد بن ابی سہل، جیسا کہ بعض مغربی مصنفین کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ براکلمان اور ہیفننگ اسی زمرے میں آتے ہیں۔
ولادت
متقدمین سوانح نگار آپ کی تاریخِ ولادت بیان نہیں کرتے، البتہ متاخرین میں فقیر محمد جہلمیؒ اور مولانا عبد الحی لکھنویؒ نے صراحت کی ہے کہ آپ ۴۰۰ھ کے دوران ’’سرخس‘‘ میں پیدا ہوئے۔ سرخس کے بارے میں نواب صدیق حسن خاںؒ فرماتے ہیں:
’’بفتحتین و سکون خاء معجمہ للبلد از خراسان است‘‘۔
اور مولانا عبد الحیؒ فرماتے ہیں:
السرخسی نسبۃ الی السرخسی بفتح السین و فتح الراء و سکون الخاء بلدۃ قدیمۃ من بلاد خراسان وھو اسم رجل سکن ھذا الموضع وعمّرہ و اتم بناء ذوالقرنین۔ (فوائد البیہ ص ۱۵)
یہ شہر تاریخ اسلام میں عرصۂ دراز تک بڑا مردم خیز رہا ہے۔ متعدد نامور فقہاء، طبیب، وزراء وغیرہ یہاں پیدا ہوئے۔ آج کل یہ شہر ایرانی روسی سرحد پر دونوں مملکتوں میں آدھا آدھا بٹا ہوا ہے۔ دریائے ہررود اس کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ (بحوالہ نذر عرشی مقالہ ڈاکٹر حمید اللہ ص ۱۲۱)
تعلیم و تربیت
دس سال کی عمر میں باپ کے ساتھ، جو تجارت پیشہ تھے، بغداد آئے۔ اس کے بعد شمس الائمہ عبد العزیز بن احمد بن نصر بن صالح الحلوانی البخاریؒ کی خدمت میں بخارا حاضر ہوئے۔ حلوانیؒ کے متعلق جمال عبد الناصر فرماتے ہیں:
ھو فقیہ الحنفیۃ کان امام اھل الرائ فی وقتہ ببخارا۔ صنف شرح المبسوط، نوادر فی الفروع والفتاوٰی، ادب القاضی لابی یوسف دفن بخاری ۴۴۸ھج۔
’’وہ احناف کے فقیہ تھے اور اپنے وقت میں بخارا اور اہل رائے کے امام تھے‘‘۔ (فروع الحنفیہ ص ۲۵۳)
حلوانی بخارا میں درس دیتے تھے۔ سرخسیؒ عرصۂ دراز تک ان کے درس میں حاضر ہوئے۔ سرخسیؒ نے اپنی شرح ’’السیر الکبیر‘‘ کے شروع میں صراحت کی ہے کہ میں نے حلوانی کے علاوہ شیخ الاسلام ابوالحسن علی بن محمد بن الحسین بن محمد الغدیؒ متوفی ۴۶۱ھ سے بھی کتاب مذکور کا درس لیا۔ نیز ان کے تیس استادوں میں ابو حفص عمر بن منصور البزار بھی ہیں، لیکن ان سے سرخسیؒ نے ’’السیر الکبیر‘‘ کا درس ان کے اس کی شرح لکھنے سے قبل لیا۔ مگر علامہ سرخسیؒ شمس الائمہ حلوانیؒ کے مشہور ترین و ممتاز ترین شاگرد ہوئے۔ آپ نہ صرف استاد کے درسگاہ ہی میں جانشین ہوئے بلکہ ان کے لقب ’’شمس الائمہ‘‘ کے بھی زبانِ خلق سے وارث قرار پائے۔
فقہی مقام و مرتبہ
فقہاء کے سات طبقات ہیں: (۱) مجتہدین فی الاصول (۲) مجتہدین فی المذہب (۳) مجتہدین فی المسائل (۴) اصحابِ تخریج (۵) اصحابِ ترجیح (۶) متمیزین بین الاقوی والقوی والاضعف والضعیف (۷) مقلدین محض۔
کمال پاشازادہؒ نے سرخسیؒ کو طبقۂ ثالثہ یعنی مجتہدین فی المسائل میں شمار کیا ہے جیسے ابوبکر خصافؒ، طحاویؒ، ابوالحسن الکرخیؒ، شمس الائمہ الحلوانیؒ، فخر الاسلام بزدویؒ، فخر الدین قاضی خاں صاحبؒ، ذخیرہ و محیط شیخ طاہر احمدؒ مصنف خلاصۃ الفتاوٰی، یہ سب حنفی ہیں جو امام کی مخالفت نہ اصول میں کرتے ہیں اور نہ فروع میں بلکہ امام کے قواعد سے ان مسائل کا استنباط کرتے ہیں جن میں امام سے کوئی روایت نہیں ہے۔
سند
فتاوٰی شامیؒ میں علامہ سرخسیؒ کی سند یوں درج ہے:
شمس الائمہ سرخسی عن شمس الائمہ الحلوانی عن القانی ابی علی النسفی عن ابی بکر محمد بن الفضل البخاری عن ابی عبد اللہ المزبونی عن ابی حفص عبد اللہ بن احمد بن ابی حفص الصغیر عن والدہ ابی حفص الکبیر عن الامام محمد بن حسن الشیبانی عن امام الائمہ سراج الامۃ ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی عن حماد بن سلیمان عن ابراہیم النخعی عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعودؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن امین الوحی جبریل عن الحکم العدل جل جلالہ تعالیٰ و تقدست اسماءہٗ۔ (شامی ص ۴ ج ۱)
کرامات
(۱) مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب آپ کو ظالم نے قید کر کے اوزجند کی طرف بھیجا تو راستہ میں جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے ہاتھ پاؤں سے خودبخود بند کھل جاتے۔ آپ وضو یا تیمم کرکے پہلے اذان پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دیتے۔ اس وقت پہرے دار سپاہی دیکھتے کہ ایک جماعت سبز پوشوں کی آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہی ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو سپاہیوں کو کہتے آؤ تم مجھے باندھ لو۔ سپاہی کہتے خواجہ ہم نے تمہاری کرامت دیکھ لی ہے اب ہم تم سے ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ اس پر خواجہ جواب دیتے کہ میں حکمِ خدا کا مامور ہوں پس میں اس کا حکم بجا لایا تاکہ قیامت کو شرمندہ نہ ہوں، اور تم اس ظالم کے تابعدار ہو پس چاہیئے کہ تم اس کا حکم بجا لاؤ تاکہ اس کے ظلم سے خلاص پاؤ۔
(۲) جب آپ شہر اوزجند پہنچے تو ایک مسجد میں مؤذن نے تکبیر کہی۔ آپ نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوئے، امام نے آستین کے اندر ہی ہاتھ رکھ کر تکبیر تحریمہ کہی، آپ نے پچھلی صف سے آواز دی کہ پھر تکبیر کہنی چاہیئے، امام نے پھر اسی طرح آستین میں ہاتھ رکھ کر تکبیر کہی۔ پس اس طرح تین دفعہ ردومدح ہوا، چوتھی دفعہ امام نے منہ پھیر کر کہا، شاید آپ امام اجل سرخسیؒ ہیں۔ آپ نے کہا، ہاں۔ امام نے کہا کہ تکبیر میں کچھ خلل ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں لیکن مردوں کے لیے ہاتھ آستین سے باہر نکال کر تکبیر کہنا سنت ہے، پس مجھ کو اس کے ساتھ اقتداء کرنے سے عار ہے جو عورتوں کی سنت کے ساتھ نماز میں داخل ہو۔
(۳) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ طالب علم آپ سے اس کنویں پر جس میں آپ قید تھے سبق پڑھ رہے تھے۔ ایک طالب علم کی آواز آپ نے نہ سنی، پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ ایک نے کہا کہ وہ وضو کرنے گیا ہے اور میں بسبب سردی وضو نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا ’’عافاک اللہ‘‘ تجھے شرم نہیں آتی کہ اس قدر سردی میں تو وضو نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھ کو تو طالبعلمی کے وقت بخارا میں ایک دفعہ عارضہ شکم لاحق ہوا تھا جس سے مجھے بہت دفعہ قضائے حاجت ہوئی، پس ہر دفعہ نالہ سے وضو کرتا تھا۔ جب مکان پر آتا تھا تو میری دوات بسبب سردی کے جمی ہوئی تھی، پس میں اس کو اپنے سینہ پر رکھ لیتا جب وہ سینہ کی گرمی سے حل ہو جاتی تو اس سے تعلیقات لکھتا تھا۔ (حدائق الحنفیہ ص۲۰۵)
تعلیمی رفقاء
دورِ تعلیم میں آپ کے رفقاء یہ تھے: (۱) شمس الائمہ ابوبکر زنجری (۲) محمد بن علی زنجری (۳) ابوبکر محمد بن حسین (۴) فخر الاسلام علی بن محمدبن حسین بزدوی (۵) صدر الاسلام (۶) ابوالسیر محمد بن محمد بزدوی کے بھائی (۷) قاضی جمال الدین (۸) ابو نصر احمد بن عبد الرحمان (۹) علی بن عبد اللہ الخطیبی رحمہم اللہ تعالیٰ۔
تلامذہ
علامہ سرخسیؒ کے تلامذہ میں مشہور بزرگوں کے اسماء گرامی یہ ہیں: (۱) علی بن حسین سغدی (۲) رکن الاسلام مؤلف مختصر مسعودی (۳) ابوالحسن سغدی مؤلف دراوی شرح سیر کبیر۔ سغد، سمرقند کے نواح میں ہے (۴) مسعود بن حسین (۵) عبد الملک بن ابراہیم مؤلف طبقات حنفیہ و شافعیہ (۶) محمود بن عبد العزیز اوزجندی (۷) رکن الدین خطیب (۸) مسعود بن حسین کتانی (۹) محمد بن محمد بن محمد رضی الدین سرخسی مصنف محیط (۱۰) عثمان بن علی بن محمد بن محمد بن علی ۴۴۵ھ تا ۵۵۲ھ (۱۱) حیرۃ الفقہاء عبد الغفور بن نعمان کردری (۱۲) ظہیر الدین حسین بن علی مرغنیانی (۱۳) ابوعمر عثمان بن علی بیکندی (۱۴) برہان الائمہ عبد العزیز بن عمر بن بازہ۔
تصانیف
علامہ سرخسیؒ کی جو کتب چھپ چکی ہیں ان میں سے (۱) المبسوط (۲) شرح السیر الکبیر (۳) کچھ حصہ شرح السیر الصغیر (۴) اصول فقہ للسرخسی (۵) شرح الزیادات۔ اور جو کتب مخطوطوں کی شکل میں محفوظ ہیں ان میں سے (۱) اشراط الساعۃ فی مقامات التیامہ (۲) شرح الجامع الکبیر (۳) شرح الجامع الصغیر۔ اور کچھ ناپید ہیں مثلاً (۴) شرح مختصر الطحاوی (۵) شرح نکت زیادات الزیادات۔ کشف الظنون میں ایک کتاب ’’الفوائد‘‘ کو بھی سرخسیؒ کی تالیف بتایا گیا ہے۔ ’’المبسوط‘‘ کا تعارف انشاء اللہ العزیز ایک مستقل مقالہ کی صورت میں الگ تحریر کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں دیگر کتابوں کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔
شرح السیر الکبیر
اس کتاب کے متعلق ابن قطلوبغاؒ لکھتے ہیں:
’’ان کی ایک کتاب ’’شرح السیر الکبیر‘‘ دو ضخیم جلدوں میں ہے۔ یہ کتاب انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس وقت املاء کرانا شروع کی جب وہ کنویں میں قید کاٹ رہے تھے۔ باب الشروط تک پہنچے تو رہائی ہو گئی اور امام سرخسیؒ آخری عمر میں فرغانہ چلے گئے جہاں کے حکمران امیر حسنؒ نے انہیں مقام و مرتبہ سے نوازا۔ پھر طلباء آپ تک وہاں پہنچے اور باقی ماندہ کتاب انہوں نے فرغانہ میں املاء کرائی‘‘۔ (بحوالہ کتاب التراجم ص ۵۳)
یہ دراصل امام محمد کی ’’السیر الکبیر‘‘ کی، جو قانون بین الممالک کی ایک اہم کتاب ہے جس کا یونیسکو کی جانب سے ترجمہ بھی ہو رہا ہے، شرح ہے۔ جو امام سرخسیؒ نے قید کے آخری دور میں املاء کرانی شروع کی۔ اسے دائرہ المعارف حیدر آباد نے ۱۴۰۸ صفحوں کی چار ضخیم جلدوں میں شائع کیا ہے اور اب ایک نیا ایڈیشن مصر میں بھی چھپ رہا ہے۔
سرخسیؒ کی کتاب الشروط تک جو چوتھی جلد کے ص ۶۰ سے شروع ہوتا ہے یعنی ۱۲۸۰ صفحات کے اختتام تک پہنچے تھے کہ بالآخر انہیں رہائی ملی۔ مابقی املاء کے ۳۲۸ صفحات انہوں نے مرغنیاں پہنچ کر دس دن میں مکمل کرائے۔ اس کتاب میں مصنف نے امام محمدؒ کے اصول و اساسات کے پیشِ نظر فقہی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اس کتاب میں جہاد و قتال اور صلح و جنگ کے طریقے، غیر مسلم اقوام سے تعلقات اور تجارت وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔ اسلام کے بین الاقوامی زاویۂ نگاہ کو معلوم کرنے کے لیے یہ کتاب بڑی ضروری ہے۔
شرح السیر الصغیر
یہ جامع الصغیر فی الفروع محمد بن حسن الشیبانی الحنفی المتوفی ۱۸۷ھ کی شرح ہے جس میں ۱۵۳۲ مسائل ہیں۔ ۱۷۰ اختلافی مسائل، ۲ مسائل میں قیاس و استحسان کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے متعلق کہا گیا ہے:
لا یصلح المرء للفتوی ولا للقضاء الا اذا علم مسائلہ۔
’’کوئی شخص فتوٰی اور قضا کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک اس کتاب کے مسائل کا علم حاصل نہ کر لے۔‘‘
اس شرح کی بندہ کو تلاش تھی، الحمد للہ استاذ محترم حضرت مولانا عبد الحمید سواتی مدظلہ العالی نے نشاندہی فرما دی ہے کہ کندیاں شریف کے کتب خانہ میں اس کا نسخہ موجود ہے، یہ کتاب بھی امام سرخسیؒ نے قید کے دوران املاء کرائی۔
اصولِ فقہ
یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور بعض مدارسِ عربیہ میں داخلِ نصاب بھی ہے۔ یہ کتاب بھی آپ نے قید خانہ میں اس لیے املاء کرائی تھی تاکہ امام محمدؒ کی کتابوں کی شرح میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اصول اور اساسات معلوم ہو جائیں، یہ کتاب دو جلدوں میں احیاء المعارف حیدر آباد نے شائع کی ہے۔
صفۃ اشراط الساعۃ و مقامات القیامۃ
ایک زمانہ میں ان کے استاد حلوانیؒ نے اس کتاب پر درس کا سلسلہ شروع کیا۔ علامہ سرخسیؒ نے اس املاء کو قلمبند کیا۔ خوش قسمتی سے یہ کتاب محفوظ رہ گئی۔ بقول جناب ڈاکٹر حمید اللہ اس کا واحد نسخہ پیرس کے عمومی کتب خانہ میں عربی نمبر ۲۸۰۰ مجموعہ ورق ۴۴۲ ب تا ۴۶۵ ب ۲۱ سطروں والی بڑی تقطیع پر موجود ہے۔ اس کی تمہید کا ایک فقرہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یوں نقل کیا ہے کہ:
سئل الامام شمس الائمہ الحلوانی عن مقامات القیامۃ و قیام الساعۃ ھل ورد فیھا حدیث صحیح؟ قال ورد ۔۔۔ وھذا الحدیث الواحد اسلم الاحادیث فی ذلک وھو ما حدثنی الفقیہ ابوبکر محمد بن علی سنۃ خمس و اربع مائۃ ۔۔۔
’’امام حلوانیؒ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کی علامات کے بارے میں کیا کوئی صحیح حدیث وارد ہوئی ہے؟ فرمایا، ہاں، اور یہ ایک حدیث اس بارے میں تمام احادیث سے زیادہ سلیم ہے اور یہ وہ روایت ہے جو مجھ سے امام ابوبکر محمد بن علیؒ نے ۴۰۵ھ میں بیان کی۔‘‘
تاریخ سے یہ دقیق اعتنا سرخسیؒ نے اپنے استاد سے سیکھا جسے انہوں نے خود بھی جاری رکھا۔
شرح الجامع الکبیر
اس کا ایک حصہ مصر میں مخطوطے کی شکل میں موجود ہے۔
ان کے علاوہ سرخسیؒ نے امام محمدؒ کی کتاب زیادات اور زیادات الزیادات کی شرحیں بھی اسی قید خانہ میں املاء کرائیں۔ ان میں سے ’’زیادات الزیادات‘‘ احیاء المعارف حیدر آباد کی طرف سے چھپی ہے۔ علامہ سرخسیؒ نے ۴۹۰ نکتے بیان فرمائے اور قید میں املاء کرائے ہیں۔ پہلا جملہ اس کا ہے ’’الحمد لولی الحمد ومستحقہ‘‘۔
شرح مختصر الطحاوی
اس کتاب کا تفصیلی ذکر کہیں نہیں مل سکا۔ یہ نایاب کتاب ہے۔ البتہ سوانح نگاروں نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ چنانچہ حاجی خلیفہؒ فرماتے ہیں ’’شرح مختصر الطحاوی فی خمسۃ اجزاء‘‘ (کشف الظنون ص ۱۶۲۸)
ابن قطلوبغاؒ نے بھی ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کا ایک حصہ دیکھا ہے (تاج التراجم ص ۵۲)۔ ان کتب کے علاوہ علامہ کی شرح النفقات للخصافؒ شرح ادب القاضی للخصاف، شرح ادب القاضی للخصاف کا ذکر مولانا ابو الوفا افغانی نے کیا ہے۔ نیز مختلف ابواب کی شکل میں بھی تحریری مواد کا ثبوت ملتا ہے جیسے کتاب السرقہ، کتاب الکسب، مگر وہ مبسوط ہی کا حصہ معلوم ہوتی ہیں۔
علامہ کی ان تمام کتب کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ عموماً سرخسیؒ جب کبھی امام محمدؒ کی کسی ذاتی رائے کی توجیہہ کرتے ہیں تو فقہ کے اصول کلیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں سرخسیؒ سے متعلق مقالہ نگار ہیفننگ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ سرخسیؒ اپنی اس کوشش کے باعث ممتاز ہیں کہ وہ قانون کے عام اساسات و اصول کلیہ کو نمایاں کرتے ہیں۔
قید و بند کی صعوبتیں
آپ بڑے حق گو تھے۔ آپ نے بادشاہ کے سامنے کلمۂ حق کہا جس سے وہ ناراض ہوگیا اور آپ کو قید کر دیا اور اوزجند میں ایک کنویں کے اندر بند کر دیا جس میں آپ مدت تک رہے۔ علامہ عبد الحیؒ فرماتے ہیں:
وھو فی الجب محبوس بسبب کلمۃ تصلح بھا الامراء۔
’’وہ کنویں میں ایک کلمۂ حق کی وجہ سے بند کر دیے گئے جس کے ذریعے وہ حکام کی اصلاح چاہتے تھے۔‘‘
اور سیر النبلاء میں حضرت ملا علی القاری کے حوالے سے لکھا ہے:
و فی طبقات القاری املا المبسوط نحو خمسۃ عشر مجلدا وھو فی السجن باوزجند محبوس بسبب کلمۃ کان فیھا من الناصحین۔
نیز تاج التراجم، الاعلام خیر الدین زرکلی، تاریخ الفقہ الاسلامی، مفتاح السوادہ میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ لیکن اصل وجہ پر بہت کم روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام زیر لفظ ’’سرخسی‘‘ میں ہیفننگ نے لکھا ہے:
’’غالباً انہیں اس لیے قید کیا گیا کہ ام ولد کے نکاح کے متعلق انہوں نے حکمرانِ وقت کے فعل پر شرعی نقطۂ نظر سے اعتراض کیا تھا۔‘‘
لیکن بقول ڈاکٹر حمید اللہ یہ وجہ قابل قبول نہیں اس لیے کہ سارے مآخذ صراحت کرتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض رہائی کے بعد کا واقعہ ہے۔ دوسری وجہ قید کا حوالہ ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں کہ استنبول کے ’’عمومی ترکی تاریخ‘‘ کے پروفیسر احمد ذکی ولیدی طوغان نے ایک مرتبہ ان سے زبانی گفتگو کے دوران یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اس زمانہ میں ابو نصر احمد بن سلیمان الکاسانی نامی ایک بدطینت شخص تھا۔ وہ قاضی القضاۃ پھر وزیر رہا۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ اس طرح کا حوالہ خود مبسوط میں بھی آتا ہے اگرچہ نام کی تصریح نہیں۔
قال فی اخرہ ’’انتھی املاء العبد الفقیر المبتلی بالھجرۃ الحصیر المحبوس من جھۃ السلطان الخطیر باغراء کل زندیق حقیر‘‘۔
اس سلسلے میں مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم سابق صدر شعبۂ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کا خیال شاید صحیح ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں صلیبی جنگوں کے باعث عالمِ اسلام میں بحران تھا اور ہر روز نئے نئے ٹیکس لگ رہے تھے اور بے پناہ مظالم ہو رہے تھے۔ سرخسیؒ نے بعض ٹیکسوں کو ناجائز قرار دیا۔ گویا ’’عدم ادائیگی محاصل کی تحریک‘‘ کی قیادت کی تھی۔ اس پر قید ناگزیر تھی اور ڈاکٹر صاحب نے سرخسیؒ کے ایک سوانح نگار محمود بن سلیمان الکفوی کا تائیدی حوالہ بھی دیا ہے۔
آپ کتنی مدت قید رہے؟ مبسوط اور دیگر کتب جو آپ نے قید میں املاء کرائیں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ۴۶۶ھ سے ۴۸۰ھ تک قید میں رہے یعنی تیرہ چودہ سال کی مدت۔ آپ صرف کنویں ہی میں اتنی مدت نہیں رہے بلکہ آپ کی تصانیف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ مختلف وقتوں میں مختلف مقامات میں قید رکھے گئے۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بھی فرماتے ہیں:
’’ان سارے اقتباسات سے گمان ہوتا ہے کہ اولاً واقعی آپ کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، پھر ان کی ریاضت اور صبر سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ حالت میں اصلاحِ عمل آئی ہو گی اور ایک چھوٹے حجرے میں بند رہے۔ اس کے بعد کسی افسر اور معتمد حکومت کے مکان میں زیرنگرانی رکھے گئے اور دوبارہ قلعہ میں لائے گئے شاید اس لیے کہ ملک کی آئے دن کی جنگوں جھگڑوں میں دشمن انہیں نہ لے اڑیں یا برہمی کو کم کرنا مقصود تھا بالآخر رہا کئے گئے۔‘‘ (نذر عرشی ص ۱۲۵)
وفات سرخسیؒ
اعداد کے حساب سے آپ کی تاریخ وفات ’’شمس ملک اور مجتہد اولیاء‘‘ سے نکلتی ہے یعنی ۴۸۳ھ۔ بعض جگہ ’’فی حدود تسعین‘‘ اور بعض جگہ ’’حدود خمس مائۃ‘‘ کا ذکر ہے۔ علامہ خضریؒ آپ کا سنِ وفات ۴۸۲ھ اور نواب محمد صدیق حسن خان بھوپالی ۴۹۴ھ بیان کرتے ہیں۔ جبکہ تحفۃ الفقہاء میں ۴۳۸ھ تک بھی لکھا ہے جو بالکل غلط ہے، شاید کتابت میں بجائے ۸۳ کے ۳۸ لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ سب مبہم اور تخمینی الفاظ ہیں۔ ابن قطلوبغا اور کفوی نے صراحت کی ہے ’’فخرج فی اخر عمرہ الی فرغانہ‘‘۔ اور خود علامہ سرخسیؒ کے بیان کے مطابق وہ ۴۸۰ھ میں علاقہ فرغانہ کے شہر مغنیان میں جا ٹھہرے تھے لہٰذا سالِ وفات ۴۸۳ھ زیادہ قرینِ قیاس ہے۔ مولانا عبد الحی نے ماہ جمادی الاولی کی بھی صراحت کی ہے اور ماخذ کشف الظنون ہے۔ مبسوط کے مخطوطوں میں بھی تاریخوں کا یہ اختلاف پایا جاتا ہے مگر بالآخر یہ تین تاریخیں ہی سامنے آتی ہیں، دو تخمینی اور ایک معین۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحبؒ نے بھی ۴۸۳ھ کو ترجیح دی ہے (نذرعرشی ص ۱۳۲)۔
عصرِ حاضر کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ
حافظ محمد اقبال رنگونی
کچھ عرصہ سے ایڈز نامی بیماری نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں اور مفکروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہر مفکر اس کے سدباب کے لیے کوشاں ہے اور تحقیق اور ریسرچ کے ذریعہ اس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس بیماری کے پیدا ہونے کی دوسری وجوہات سے قطع نظر تمام ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ لواطت پرستی اور غیر فطری عمل اس بیماری کو پیدا کرنے کا سبب ہے، اسی لیے تمام ہسپتالوں اور ٹی وی کے اشتہاروں میں خبردار کیا جاتا ہے کہ غیر فطری عمل سے اجتناب کیا جائے۔
لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ دوسری جانب اس بیماری کو وسیع کرنے کے پروگرام بھی تیار کیے جاتے ہیں جس عمل کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ برطانوی معاشرہ کے یہ ناسور اسی عمل کے پھیلاؤ کے لیے نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ اسے قانونی بنا کر اس کی مالی امداد کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ ۱۶ سال کی عمر کو غیر فطری حرکت کے لیے موزوں قرار دے کر سابقہ قانون کو ختم کرنے کے لیے بل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ روزنامہ مرر ۴ اکتوبر ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ:
’’برائیٹن میں لیبر پارٹی کی کانفرنس کے موقعہ پر یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ ہم جنس پرستی کے لیے ۲۱ سال کی عمر کی قید ختم کر کے ۱۶ سال کر دی جائے۔ تقریباً پونے چار لاکھ ووٹ کے ذریعے یہ بات تسلیم کی گئی کہ عمر کا یہ امتیاز ختم کر دیا جائے۔ اس مطالبہ کو برطانوی ایم پی مسٹر کرس اسمتھ نے پیش کیا ہے۔‘‘
اس کانفرنس کو ختم ہوئے چند ہفتے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ حزبِ اختلاف کے مشہور ایم پی ٹونی بین نے برطانوی دارالعوام میں بل بھی پیش کر دیا۔ مانچسٹر ایوننگ نیوز ۶ نومبر کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ:
’’لیبر پارٹی کے ایم پی مسٹر ٹونی بین نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا ہے جس کا مقصد ہم جنس پرستوں کے لیے عمر کی قید ختم کرنا ہے۔ لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر بھی تقریباً ۴ لاکھ لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے تھے اور یہ قانون پاس کیا تھا کہ جب لیبر پارٹی برسراقتدار آئے گی تو ایسا ہی کرے گی۔ لیبر پارٹی کے سربراہ حزب اختلاف کے قائد نیل کینک کو اس بل کے پیش کرنے کی وجہ سے سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ٹونی بین نے بغیر کسی تبادلۂ خیال کے یہ بل پیش کر دیا تھا۔‘‘
ہمیں لیبر پارٹی کے سربراہ سے صرف یہ کہنا ہے کہ جب سالانہ کانفرنس کے موقع پر یہ مطالبہ پیش کیا تھا اور لاکھوں لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی تو اب تبادلۂ خیال کیوں اور کیسا؟ اگر یہ موقف اور مطالبہ انتہائی بے حیا و فحش تھا تو اس وقت اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا۔ انہیں چاہیئے کہ شرمندگی کے بجائے اعتراف و اقرار اور کھلے بندوں میدان میں آجائیں، اس لیے کہ اس حمام میں سب ہی ننگے ہیں کیا ایم پی اور کیا عوام۔
؏ بے شرموں کو شرم آئی خدا خیر کرے
لیبر پارٹی کے اس ذلیل موقف اور دوسرے بے حیاؤں کے مطالبات پر مانچسٹر شہر کی کونسل ایسے بدقماشوں کے لیے ایک عظیم ادارہ تعمیر کرنے میں مصروف ہو چکی ہے۔ مانچسٹر ایوننگ نیوز ۹ دسمبر ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں خبر دیتا ہے کہ:
’’مانچسٹر شہر کی کونسل نے ۳ لاکھ پونڈ کی مالیت سے ایک ایسی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو ہم جنس پرستوں کے لیے مخصوص ہو گا۔ کونسل کی ایک ہم جنس پرست کونسلر مس ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ مانچسٹر میں ہر ۲۰ عورتوں میں سے ایک اسی گروہ سے ہے اور یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ مالی کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس خطیر رقم سے بننے والے سنٹر کی وجہ سے ایسے لوگ خطرے میں نہ رہیں گے بلکہ آزاد ہوں گے۔‘‘
اس خبر پر سوائے دو چار کے کسی نے نہ تو تبصرہ کیا ہے اور نہ ہی تنقید۔ اور جس نے تبصرہ کیا بھی تو صرف اسی بات پر کہ اتنی خطیر رقم سے ہسپتال اور سڑک، سکول اور اساتذہ کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیئے، بس اس سے زیادہ کسی نے تبصرہ کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یورپی سوسائٹی میں شرم و حیا، عفت و عصمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تہذیب عصر حاضر کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بدتہذیبی و بے حیائی کی حد تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سرکاری تحفظ دیا جاتا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق باقاعدہ ان کی شادیوں کو تسلیم کیا جانے لگا۔ برطانوی اخبار ٹائم ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۹ء کی یہ خبر پڑھیئے اور یورپی تہذیب کا تماشا دیکھئے۔ اخبار لکھتا ہے کہ:
’’ڈنمارک کی حکومت نے لواطت پرستوں کی شادی کو سرکاری تحفظ دینے کا اعلان کر دیا جو یکم اکتوبر ۱۹۸۹ء سے شروع ہو چکا ہے، اس تحفظ سے فائدہ اٹھا کر دو مردوں نے آپس میں شادی کی۔ اوف کارسن اور این لارسن نے جو ۴۲ سال کے ہیں نے بتایا کہ ہماری یہ شادی کوئی معمولی شادی نہ تھی بلکہ دنیا میں ہم پہلے دو ہیں جن کی شادی کو باقاعدہ حکومتی سطح پر تسلیم کیا گیا اور رجسٹرار کے دفتر سے شادی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا۔ یہ شادی کوپن ہیگن کے ٹاؤن ہال میں مزید ۱۰ جوڑوں کے ساتھ رچائی گئی اور بڑے زور و شور سے اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ آئندہ اس قسم کی شادی عبادت گاہوں میں بھی ہوا کرے گی اور چرچ بھی ایسی شادی کو تسلیم کرے گا۔ انہوں نے اخباری رپورٹر کو بتایا کہ آج کے بعد ہم اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب کو یہ کہہ سکیں گے کہ ہم دونوں قانونی طور پر شادی شدہ ہیں۔ اخبار کے مطابق یورپی ممالک کے تمام ہم جنس پرستوں نے اس خبر و قانون پر بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ و مطالبہ کیا کہ یورپ کے دوسرے ممالک بھی اسے تسلیم کریں اور اس سلسلے میں یورپی پارلیمنٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جائیں گے۔‘‘
یورپی ممالک کے مفکروں، کونسلروں اور ایم پی کی طرف سے غیر اخلاقی حرکت کے نفاذ پر یہ اصرار ان کی بیمار ذہنیت کا پتہ دے رہی ہیں اور پورا معاشرہ عفت و عصمت، شرم و حیا، طہارت و پاکبازی کے معانی و مفاہیم سے بالکلیہ محروم ہو چکا ہے۔ اسی معاشرہ ہی کے وہ افراد ہیں جو رشدی کی شیطانیت کی حمایت میں مصروف و مشغول ہیں کیونکہ یہ حرام کاری اور خلاف وضع فطری عمل دونوں کے دلدادہ ہیں اور ہر اخلاقی امور کی مخالفت ان کا وطیرۂ زندگی بن چکا ہے۔ یہ لوگ فطرتِ سلیمہ اور اخلاقِ عالیہ کے تمام ضوابط سے نہ صرف محروم بلکہ شدت سے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے شیطانی افراد سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فطرتِ سلیمہ اور اللہ کے دین کے معیار کو سامنے رکھیں گے۔
جب خدا کا تصور اور اس کے احکام کا پاس و لحاظ ختم ہو جائے، زندگی کو حیوانی بلکہ اس سے بھی بدتر طریقے پر گزارنے کا چلن عام ہو جائے تو پھر اخلاقی اقدار باقی نہیں رہتے۔ جب شہوات کی حکمرانی دل و دماغ پر مستحکم ہو جائے تو پھر شرافت، شرم و حیا کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور بالآخر فطرت کی خلاف ورزی پر وہ سزا دی جاتی ہے جس سے بچنا ناممکن بن جاتا ہے۔ یہی وہ ایڈز ہے جو عذابِ الٰہی کی صورت میں ظاہر ہو کر ہر بے حیا پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہے (العیاذ باللہ)۔
چرچ اور پادریوں کی اخلاقی زبوں حالی
مانچسٹر کے علاقہ برانزوک کے چرچ کی جانب سے یہ خبر ملی ہے کہ ہفتہ میں دو دن God and Sex کے عنوان پر درس دیا جائے گا۔ اس عنوان کے تحت زنا بالجبر، زنا بالرضا، ہم جنس پرستی، چھوٹے بچوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات اور طلاق جیسے اہم موضوعات ہوں گے۔ علاوہ ازیں ویڈیو فلم بھی دکھائی جائیں گی اور ایک ماہر جنسیات کو بطور خاص مدعو کیا جائے گا۔ مارٹن گوڈر کا کہنا ہے کہ یہ موضوعات ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ جب خدا نے شہوت پیدا کی تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی قدرت سے خوب نفع لیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جب مجھے اپنی گاڑی کے لیے بہتر سہولت حاصل کرنی ہو تو میں گاڑی بنانے والے کی ہینڈ بک دیکھوں گا۔ اسی طرح زندگی کا صحیح لطف حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی کتاب یعنی بائبل دیکھنی ہو گی۔ اخبار نے اس پر یہ سرخی جمائی ہے Church Guide to Good Sex (مانچسٹر ایوننگ نیوز)
پادری صاحب کی اس بات سے تو شاید ہی کسی کو اختلاف ہو گا کہ یورپی تہذیب میں Sex کا موضوع بہت ہی سستا اور عام ہے۔ یہاں کے سکولوں میں اس موضوع پر لیکچر کے علاوہ فلم بھی دکھائی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی سکول جانے کی بجائے ہسپتال پہنچ جاتی ہے اور ’’کنواری ماں‘‘ کے نام سے یاد کی جاتی ہے کیونکہ اس تہذیب میں جو شخص جتنا بے حیا و بے شرم ہو گا اتنا ہی مہذب اور جدت پسند کہلاتا ہے اور کونسل سے لے کر حکومت تک اس کی حوصلہ افزائی میں پیش پیش رہتے ہیں۔ یہاں ایک عام آدمی سے لے کر ایم پی تک محبوبہ اور گرل فرینڈ رکھنے کو معیوب نہیں سمھجتا بلکہ بڑے بڑے ایم پی کے ناجائز تعلقات منظرِ عام پر آ چکے ہیں، اور برطانوی ٹیلی ویزن کی ایک مشہور و معروف خبرنامہ پڑھنے والی این دائمنڈ تو ناجائز بچے کی ماں بن کر بھی برطانوی ٹی وی پر پوری آن و بان سے موجود ہیں۔ مانچسٹر ایوننگ نیوز نے ۵ نومبر کی اشاعت میں بچوں کی اخلاقی حالت کا سروے کرنے کے بعد رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سب بچوں کا خیال ہے کہ ان کے والدین کو اس جنس پرستی کے موضوع پر بتانا چاہیئے، اس کے بعد ٹیچرز کو بتانا چاہیئے، یوں تو دوست احباب، لٹریچر، رسالے سے بہت سی معلومات مل جاتی ہیں۔
اس کا نتیجہ روزانہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ کس خطرناک صورت میں نکلتا ہے، ہزاروں لڑکیاں کنواری مائیں بن جاتی ہیں، بے شمار بچوں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، راہ چلتی ہوئی عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک ۸۰ سالہ بوڑھی عورت بھی ان کے ہوس کا شکار بن جاتی ہے، مگر حکومت اور برطانوی مفکرین مجبور اور بے بس ہیں کہ اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں پر پابندی لگا سکیں۔ پادری صاحب اچھی طرح اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ چرچ اور گرجاگھروں میں کیا کچھ ہوتا رہا اور ہوتا ہے۔۔۔۔
پادری صاحب کی خدمت میں صرف اتنا عرض کریں گے کہ چرچوں اور گرجاگھروں کو غیر اخلاقی حرکات کی آماجگاہ نہ بنائیں۔ یہاں Sex کے موضوعات پر درس دینے کے بجائے اخلاق و شرافت کے اصول سمجھائیں اور برطانوی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اس قسم کی تمام مخرب اخلاق و حیا سوز رسائل و جرائد، کتاب و فلم پر کڑی پابندی عائد کر کے خلافِ قانون قرار دے اور اس کے مرتکب کا خدائی قانون کی روشنی میں فیصلہ کرے تاکہ صحیح معنوں میں ایک اچھی سوسائٹی کہی جائے۔
اسلامی نظامِ تعلیم کے خلاف فرنگی حکمرانوں کی سازش
شریف احمد طاہر
مسلم قوم اس کرۂ ارض پر چودہ سو سال سے جاوداں ہے۔ اس کے سفر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رہنمائی میں ہوا اور طاقت و توانائی خلفاء راشدینؓ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ، علماء کرامؒ، مصلحینِ امتؒ اور صوفیائے عظامؒ سے حاصل ہوتی رہی۔ جب پرچمِ اسلام کو بنو امیہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو انہوں نے اس کو چین اور اسپین تک لہرایا۔ فرانس (کوہ پارنیز) کی سرحدوں کو عبور کیا۔ کرۂ ارض کے مکینوں کو حیاتِ نو کا پیغام دیا اور علوم و فنون کی سرپرستی کی اور خلفاء بنو امیہ کا اسپینی دور علمی و سیاسی دونوں اعتبار سے عہدِ زریں کہلایا۔
جب یہ شمعٔ فروزاں بنو عباس کے ہاتھ میں آئی تو علوم و فنون کو جلا ملی، نئی نئی ایجادات ہوئیں، جدید اصول مرتب ہوئے، تجربہ گاہیں اور رصدگاہیں تعمیر ہوئیں، بیت الحکمت کی بنیاد پڑی، دارالترجمہ قائم ہوا، اور جو علوم و فنون سربستہ راز تھے اور جسے عیسائی دنیا گمراہی و ضلالت کا پلندہ تصور کرتی تھی اسے مسلمانوں نے نسخۂ کیمیا بنا کر پیش کیا جس سے خود عیسائیوں نے استفادہ کیا۔ بنو عباس نے اپنے دورِ عروج میں خود علمی، دینی، تمدنی اور ثقافتی ہر میدان میں دنیا کی رہنمائی کی۔
اور دورِ زوال جس میں طاقت و قوت کے محور ترک و یالمہ اور سلجوقی ترک بن گئے تھے، شمع کو روشن رکھا، علوم و فنون کو عام کیا، دینی احساس کو بیدار کیا۔ خاص طور سے ساحقہ، ملک شاہ سلجوقی اور اس کا وزیر نظام الملک طوسی اس میدان میں فائق اور عظیم صلاحیتوں کے مالک ثابت ہوئے۔ علم کی شمع روشن رکھنے کے لیے درسگاہیں بنوائیں، فضلاء اور ماہرین کے لیے مسندِ درس قائم کی، طلبہ کے لیے جدید طرز کی سہولتیں، قیام و طعام فراہم کیے، ان کے لیے وظائف مقرر کیے اور مدارس کا جال بچھا دیا۔
الحاکم بامر اللہ نے سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا، پھر استاذ ابوبکر فورک کے لیے نیشاپور میں ایک مدرسہ تعمیر ہوا اور دوسرا مدرسہ بہیقیہ کے نام سے تعمیر ہوا جس کے مدرس اعظم ابوالقاسم اسفرائنی تھے اور اس میں امام الحرمین اور امام غزالیؒ کے استاذ اپنے والد کے انتقال کے بعد داخل ہوئے۔ محمود غزنویؒ نے دارالسلطنت غزنین میں مدرسہ قائم کیا اور فتوحاتِ ہند کا ایک قیمتی حصہ اس پر صرف کر دیا۔ جاگیریں وقف کیں، غزنویؒ کے بھائی امیر نصر بن سبکتگینؒ نے بھی نیشاپور میں مدرسہ بنایا جس کا نام سعیدیہ رکھا۔ اس کے بعد ہی نظام الملک نے مدارس کا جال بچھایا اور انہیں نظامیہ بغدادیہ کے ماتحت رکھا۔ ابو نصر صباغؒ، شیخ جمال الدین شیرازیؒ، علی بن مظفرؒ، امام عبد اللہ الحسین طبریؒ، قاضی ابو محمد شیرازیؒ، امام ابو حامد غزالیؒ اور ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالیؒ جیسے حکماء اسلام اور ماہرین اس مدرسہ میں تدریس کے فرائض پر فائز رہتے، اس کے ماتحت نظامیہ کا ایک طویل جال بچھا دیا گیا۔ نیشاپور، اصفہانی، مرو، خوزستان، موصل، جزیرہ ابن عمرؓ، آئل، بصرہ، ہرات، بلخ، ملوس قابل ذکر ہیں جس میں ابوالمعالی امام الحرمین ابو حامد غزالیؒ، ابوالمعالی نیشاپوریؒ وغیرہ مسندِ درس پر سرفراز ہوئے۔
جامعہ ازہر کی تعمیر ہوئی، جامعہ قیروان کی اساس پڑی، جامعہ زیتونہ نے نہ مٹنے والے نقوش ثبت کیے۔ ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، طلب، فلسفہ، کیمیا، علمِ نجوم، ریاضی اور جغرافیہ کی تعلیم ہوتی تھی مگر صلیبی حملوں نے اس تسلسل کو ناقابل ذکر نقصان پہنچا دیا اور ان مدارس کا رخ مغرب میں ترکی اور مشرق میں برصغیر کی طرف ہوا اور اس میں مملوک، خلجی، پٹھان، تغلق اور مغلوں نے ایک جوش اور ولولہ اور جمعیت دی اور علوم و فنون کی آبیاری کی۔
ان مدارس کی سرپرستی سیاسی تفوق رکھنے والے افراد کرتے تھے۔ مگر جب مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہوئے تو یہ نظام ان اللہ کے مخلص بندوں کے ہاتھ میں آیا جنہوں نے اس کی سرپرستی علمی اور مالی دونوں طرح سے کی اور دینی مدارس کے نظام کی داغ بیل ڈالی اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم کیا۔ دینی تعلیم کا رواج ہوا، زبان کو استحکام حاصل ہوا، اسلامی ثقافت و دین کی حفاظت کرنے میں بڑی مدد ملی۔
پھر ایک ایسا دور آیا کہ اس برصغیر پر انگریز قوم نے حیلہ و بہانہ اور مکر و فریب سے قبضہ جما لیا تھا اور اس کے بعد اس نے جس جبر و استبداد اور ظلم و سفاکی سے یہاں حکمرانی کی ہے میں اس کی مختصر داستان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ گویا ؎
وسعتِ دل ہے بہت، وسعتِ صحرا کم ہے
اس لیے دل کو تڑپنے کی تمنا کم ہے
جبکہ انگریز قوم نے یہاں کی مسلم قوم کو اپنی روایات و ثقافت، تمدن و سیاست، اور ملی جوش و خروش سے اس حد تک نا آشنا کر دیا ہے جس کا رونا علامہ اقبال مرحوم نے یوں رویا ہے ؎
کتابیں دے کے مجھ سے تیغ و خنجر چھیننے والے
تیری تعلیم سے اچھا تھا جوشِ جنوں میرا
۱۸۵۷ء سے جب اس جابر و قاہر، ظالم و کافر اور مکار قوم نے اس ملک پر زبردستی تسلط جما لیا تھا اور یہاں کی دولت، سیاست، ثقافت، معیشت، قومیت تمام چیزوں کو تباہ کر دیا تھا، اس سلسلہ میں کس کس نقصان کا ذکر کیا جائے بلکہ
؏ تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم
پھر اس نے جہاں برصغیر کے لوگوں کی جان و مال، دین و مذہب، ضمیر و خمیر اور ذہن و دماغ سب کو نقصان پہنچایا اور مسلمان قوم کو بنیادی اور ذہنی طور پر ناکارہ کرنے کا پروگرام اور جو سامان اس نے مہیا کیا وہاں اس نے اس قوم کو وہ نظامِ تعلیم دیا جس سے ملک و قوم کی دینی و مذہبی کایا پلٹ گئی۔ جبکہ انگریزی اقتدار سے قبل یہاں دینی علوم و فنون کا رواج بھی زوروں پر تھا۔ اس ملک میں سکولوں اور دینی مدارس کا یہ حال تھا کہ اس وقت کے سرکاری گزٹ کے مطابق صرف متحدہ بنگال میں مسلمانوں کے دس ہزار مدارس تھے۔ ادھر مضافاتِ دہلی میں صبح الاعشٰی قلشندی کے حوالے سے ایک ہزار عربی مدارس تھے جن میں سے ایک مدرسہ شوافع کا تھا اور باقی تمام احناف کے تھے۔ اس طرح انگریز سیاح ڈاکٹر ہملٹن جب ۱۴۹۰ء میں سندھ آیا تو اس نے سفر نامہ بعہدِ اورنگزیب میں ٹھٹھہ جیسے قصبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں مذہب اور فلسفے کا خوب چرچا ہے اور چار صد دارالعلوم ہیں۔
پھر جس وقت انگریز نے اس ملک میں اسلامی روایات اور علومِ دینیہ کے مراکز و مدارس کو مختلف تدابیر سے ختم کر دیا اور اپنا وہ مجوزہ نظامِ تعلیم رائج کر دیا جسے لارڈمیکالے نے تیار کر کے کہا تھا ’’ہماری سکولوں کالجوں میں انگریزی تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ سے انگلستانی ہوں‘‘۔ یہ آواز برسرِ اقتدار قوم کی آواز تھی، اس تعلیم سے ایسی نسلیں ابھرنی شروع ہو گئیں جو گوشت پوست کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھیں لیکن اپنے طرزِ فکر اور سوچنے کے رنگ ڈھنگ سے خالص انگریز ہی بن چکی تھیں۔ اس عیار و مکار قوم انگریز کے کیا ارادے تھے ان کے اپنے انداز میں ملاحظہ فرمائیں:
پادری جارج ای بوسٹ نے ’’پروٹسٹنٹ‘‘ فرقہ کی صد سالہ جوبلی میں یہ تقریر کی:
’’یہ زندگی کی جنگ ہے، ہمیں مسلمانوں پر فتح حاصل کرنی چاہیئے ورنہ وہ ہم پر فتح پا لیں گے۔ ہم کو عرب جانا چاہیئے، سوڈان جانا چاہیئے، وسط ایشیا کا سفر کرنا چاہیئے اور یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانے کا کام کرنا چاہیئے ورنہ مسلمان صحراؤں کو عبور کر کے آگ کی طرح پھیلیں گے۔‘‘
اور مستشرق مؤرخ دلفریڈ کائن ویل نے یوں لکھا ہے:
’’اسلام ہی پوری مغربی تاریخ اور مغرب کا واحد اور حقیقی حریف ہے۔ ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیئے کہ اسلام کا مقابلہ کیوں سخت ہے اور ماضی میں کس طرح اسلام ایک خطرہ بن کر سامنے آیا تھا اور اب وہ تقریباً نصف مسیحی دنیا پر چھایا ہوا ہے۔‘‘
مشن سکول کے بانیوں اور پادری ولیم نے اپنے مشنری مرکز کو ہدایت دی:
’’اس نظامِ تعلیم کا اصل مقصد مسلمان علماء کے وقار کو مجروح کر کے ان کے خلاف مسلم معاشرے میں نفرت و حقارت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔‘‘
اور مشنریوں کے الفاظ میں:
’’جب تک رائے عامہ ان مذہب کے ٹھیکیداروں کے خلاف نہ ہو جائے تب تک ہندوستانیوں کے درمیان مسیح کو پیش کرنا ممکن نہیں۔‘‘
برطانیہ کے وزیراعظم مسٹر گلیڈسٹون نے دارالعوام میں قرآن ہاتھ میں لے کر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ:
’’جب تک مسلمانوں کے پاس یہ ایسی ویسی کتاب موجود ہے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔‘‘
اس کے بعد قرآن کی مزید (ناقابلِ تحریر و برداشت) توہین کی۔ ایسی خرافات اور اسلام کے خلاف تعلیوں کے بعد یہ گستاخ انگریز جس پہلے بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا قرآن والے نے اس جہاز کا بیڑا فرعون کی طرح غرق کر دیا تھا۔ اور لارڈ کچز جیسے مشہور انگریز کی اسلامی دشمنی اور مسلمانوں سے عداوت تو ضرب المثل ہے۔ اسی واسطے حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسینؒ فرمایا کرتے تھے کہ:
’’روئے زمین پر عیسائیوں اور انگریزوں سے بڑا کوئی دشمن ہمارا نہیں۔ اس لیے ہم بھی انگریز کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔‘‘
اور وہی ہوا کہ ایک طرف تو اس انگریزی نظامِ تعلیم سے قوم و ملک کے اثر پذیر طبقہ کا ذہن اس طرح بنایا گیا جس طرح کہ منصوبہ تھا، اور دوسری طرف علماء پر عرصۂ حیات تنگ کیا گیا۔ ان کے ذرائع تعلیم اور تبلیغ اور مدارس کو برباد کیا گیا اور خاص طور پر ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں حصہ لینے والے علماء میں سے جو باقی رہ گئے تھے ان کو نہایت بے رحمی سے ختم کیا گیا۔
۱۸۵۷ء کے جہادِ حریت کے بعد جب حضرات مجاہدین نے دیکھا کہ ملک ہاتھوں سے گیا اور یہ خطرناک سیلاب امڈ آیا تو اب ملت کے تحفظ اور دین کی بقاء اور اس کے استحکام کے لیے کوئی دوسرا محاذ قائم کرنا ضروری ہے، تو حضراتِ شیخین مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور لارڈ میکالے کے چیلنج کا مقابلہ کرنے اور ایشیا میں مسلمانوں کی عربی زبان کے احیاء، تہذیب و تمدن کے تحفظ، ملک میں دینی استحکام و دوام کے لیے مدارس، دارالعلوم اور جامعات کا نظام قائم کیا اور یہ نعرہ بلند فرمایا:
’’ہماری تعلیم کا مقصد ایسے جوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے مسلمان ہوں جن میں اسلامی تہذیب و تمدن کے جذبات بیدار ہوں اور دین و سیاست کے اعتبار سے ان میں اسلامی شعور زندہ رہے۔‘‘
بلاشبہ دارالعلوم دیوبند ہندوپاک میں ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی تحفظ ناموس رسالتؐ و صحابہؓ اور بقائے اسلام کا ذریعہ ہے۔ علماء دیوبند کی جماعت مسلک حقہٗ کی ہمہ گیری کی وجہ سے ہر فتنہ کی مداخلت کے لیے سینہ سپر ہے۔ ان علماء نے ہر دور میں اعلاء کلمۃ الحق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کیا ہے اور اسی اسلوب اور اسی رنگ ڈھنگ میں جس رنگ میں فتنہ نے سر اٹھایا۔ ان مدارس اور درسگاہوں نے مسلمانوں کے نشوونما، اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے، اور قوم کو طاقت و توانائی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور جب تک ان مدارس کو طاقت و توانائی ملتی رہے گی اور یہ پودا برگ و بار لاتارہے گا، مسلمانوں کو اپنا تشخص اور اپنی سالمیت برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اور ان مدارس ہی کے استحکام میں ان کا وجود، تشخص اور سالمیت مضمر ہے ؎
خودی میں ڈوب جا عامل یہ سرِِ زندگانی ہے
نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا
حدودِ شرعیہ کی مخالفت - فکری ارتداد کا دروازہ
مولانا سعید احمد عنایت اللہ
اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود اور بھیانک معاشرتی جرائم، ڈکیتی، بدکاری، شراب نوشی اور قذف وغیرہ پر جو شرعی سزائیں خالقِ بشر نے مقرر فرمائی ہیں وہ پوری کائنات کے لیے سراسر رحمت ہیں۔ انسانی معاشرے میں قیامِ امن اور بشریت کی ہر دو صنف مرد و زن کی عزت و عصمت، ان کے مال و جان کی حفاظت کی ضامن ہیں، بلکہ انسانیت کے مقامِ شرافت و کرامت کی کفیل یہی حدود اللہ ہیں جن کے مبارک ثمرات کا اولین نتیجہ انسانوں کے اس دنیا میں مکمل تحفظ کی صورت میں ملتا ہے۔ ان سراپائے رحمت حدود کو دہشت گردی گرداننا کفرانِ نعمت اور صرف خدا رسول سے ہی بیزاری کا اعلان نہیں بلکہ انسانیت دشمنی اور خبثِ باطن اور ہوا پرستی کی ظاہر دلیل ہے۔
خصوصًا مملکتِ خداداد پاکستان جو صرف تنفیذِ شریعہ اسلامیہ کے لیے معرضِ وجود میں آئی۔ اس ملک میں حدود اللہ کے خلاف شر انگیزی وطنِ عزیز کی اساس کو ہلانا اور ارضِ پاک کے خلاف بغاوت کی ایک سازش ہے جس کی ابتدائی سزا یہ ہونی چاہیئے کہ پاکستانی شہریت کا حامل جو شخص اسلامی شریعت کے کسی پہلو پر طعن کرے اس سے پاکستانی شناختی کارڈ چھین لیا جائے اور پھر ملت و ملک کے اس باغی کا پورا محاسبہ کیا جانا چاہیئے۔
الحمد للہ تاسیسِ پاکستان کے آغاز سے ہنوز ہمارے عوام کی اکثریت اور ایوانوں کی غالبیت چاہے کسی جماعت سے وابستہ ہو اسلامی شریعت کی برتری پر غیر متزلزل یقین رکھتی ہے اور اپنی ملکی فلاح و بقا صرف اور صرف نظامِ اسلامی میں ہی جانتی ہے۔ کمی اس بات کی ضرور ہے کہ مسلم قومیت کا نظریہ جس کی عملی مشق کے لیے ہندوستان تقسیم ہوا اس کی عملی مشق کا موقع میسر نہ آسکا، اس کوتاہی کا ہر پاکستانی کو احساس ہے اور اس قصور کا ہر ذمہ دار کو اعتراف بھی ہے مگر اسلام سے بیزاری اور بغاوت یہ عوام اور حکمران ہر دو جہت سے ناقابلِ معافی جرم ہے اور رہا ہے۔
مگر ہمارے ملک میں چند افراد پر مشتمل ایک طبقہ فکری ارتداد کا بھی شکار ہے جو مغرب کو قبلہ و کعبہ جانتے ہوئے کبھی کبھی شرعی احکام کے خلاف بیزاری کا اظہار کرنے کی جرأت کرتا ہے اور حکومت کے بعض وزراء اور مشیر صاحبان بھی اس فتنے میں ان کے شریکِ عمل ہو کر نظریۂ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا یہ عمل خدا تعالیٰ کے غضب عمومی کو دعوت دیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ طبقہ پاکستان کی اکثریت کی غیرتِ ایمانی کو چیلنج کرتا ہے، ساتھ ساتھ یہ مغرب کے ایجنٹ حکومت کی وسعتِ نظری کی بھی آزمائش کرتے ہیں کہ کس حد تک حکومتِ پاکستان دینِ اسلام اور نظریۂ پاکستان کے خلاف بغاوت کو برداشت کر سکتی ہے۔ ملک و ملت اور انسانیت کا دشمن یہ طبقہ جسدِ ملکی کے لیے وہ ناسور ہے جس کا فوری معالجہ ناگزیر ہے، پاکستانی مسلم معاشرے کی پیشانی پر سے اس بدنما داغ کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ شریعتِ مطہرہ کے کسی پہلو پر طعن کرنے والے اور نظریۂ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے مفسد عناصر اعدائے اسلام کے کارندے ہیں۔ پاکستانی عوام اور حکومت کو ان کا محاسبہ کرنا ہو گا، آج نہیں تو مستقبل قریب میں انشاء اللہ تعالٰی۔ مذکور الصدر حضرات کی شر انگیزی کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔ روزنامہ جنگ ۲۱ دسمبر کے شمارے میں پاکستان ویمنز رائٹس کمیٹی کراچی کے حوالہ سے تحریر ہے کہ:
’’(۱) بچے کی ولادت کے وقت شہریت کے فارم میں ’’باپ‘‘ کے لفظ کے ساتھ ’’ماں‘‘ کا اضافہ ہونا چاہیئے تاکہ پیدا ہوتے ہی ہر بچہ (چاہے اس کا نسب کچھ ہو) شہریت کا حق حاصل کر لے۔
(۲) عورت کو قانون شہادت برائے حدود میں مستثنٰی کرنے کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیئے۔
(۳) زنا آرڈیننس معصوم افراد کی زندگیوں میں دہشت پیدا کر رہا ہے۔ـ‘‘
یہ ہیں بحالیٔ حقوقِ خواتین کی اختراعات و اقتراحات جن کی تحلیل کے طور پر عرض ہے کہ ایسی تجاویز پیش کرنے والے قرآن و سنت کی تعلیمات سے اگر بے بہرہ ہیں تو جان لیں کہ:
(۱) حق تعالیٰ شانہ نے تمام بشریت کو بنی آدم کا لقب دیا اور ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا۔ قرآن حکیم نے اولاد کو باپ کی طرف منسوب کرنے کی واضح ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ’’ادعوھم لاباءھم‘‘ اولاد کی نسبت ان کے باپوں کی طرف کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ’’الولد للفراش وللعاھر الحجر‘‘ بچہ تو اپنے باپ کا ہے اور بدکار کے لیے پتھر ہیں۔ یہ بھی معلوم رہے کہ صرف لعان کی صورت میں بچہ ماں کی طرف منسوب ہو گا کہ نکاح کے بعد خاوند اپنی منکوحہ بیوی کے حمل کا انکار کر دے اور بیوی حلف کے ساتھ اس سے حمل پر اصرار کرے اور یہ بھی کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے تو اس (عورت) پر خدا کا غضب ہو۔ تو انکارِ نسب کی صورت میں بچہ ماں کی طرف منسوب ہو گا اور اس ماں کا وارث بھی ہو گا۔ ایسی کوئی صورت نہیں کہ بحالیٔ حقوق کے نام پر ترویج اور بدکاری کی اشاعت کی خاطر ایسے قانون وضع ہوں کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے۔
(۲) یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شہادت ایک مقدس خدائی فریضہ اور عظیم قومی امانت ہے۔ بعض احوال میں خدا تعالٰی نے صنفِ نازک پر کرم فرمائی کرتے ہوئے عورتوں کے اس کے تحمل سے اور کچھ دیگر حالات میں بعض اہم فرائض سے رخصتیں دے رکھی ہیں۔ خواتین کو مولا کریم کا شکرگزار ہونا چاہیے، عورت کے فطری ضعف کی شریعت میں کتنی رعایت رکھی گئی ہے، نہ یہ کہ کفرانِ نعمت کے طور پر عورت کا اصرار ہو کہ وہ ضرور اس بوجھ کو اٹھائے گی۔ یہ عین رحمتِ الٰہی ہے کہ عورت کو امامتِ صغرٰی یعنی نماز کی امامت اور امامتِ مملکت کی ذمہ داری کے تحمل سے مستثنٰی قرار دیا۔
(۳) اسی طرح اسلامی حدود پر غور کریں کہ بدکار کو کوڑے لگانا یا سنگساری، چور کا ہاتھ کاٹنا، ڈاکو کا ساتھ ہی پاؤں بھی کاٹ دینا یا قتل کرنا، قاتل کی گردن اتار پھینکنا، یہ سب دہشت گردی کے خلاف مبارک جہاد ہے اور جرائم کے انسداد کا ایک ایسا سہل نسخہ ہے جسے حکیمِ مطلق نے فطرتِ انسانی کے عین مطابق تجویز فرمایا ہے تاکہ یہ حدود مفسد عنصر کا قلع قمع کر کے پراَمن معاشرے کی تخلیق کرنے میں مدد دے سکیں۔ جن سے مظلوم کی دادرسی ہوتی ہے، مجرمین کے لیے مقامِ عبرت اور شریروں کو ان کے شر سے باز رکھ کر پراَمن انسانوں کی خدمت اور برکاتِ خداوندی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حد کے نفاذ کی برکات چالیس سال کی بارش سے بھی بڑھ کر ہیں۔
تو مفسد عنصر کا قلع قمع انسانی معاشرے کے ساتھ عین رحمت ہے جس طرح کہ فاسد عضو کو مریض پر شفقت اور کمالِ رحمت کے تقاضہ سے کاٹ کر بقیہ جسد کو مامون و محفوظ بنایا جائے، اس میں کسی کی حق تلفی کیسے ہے؟ نہ مردوں کی، نہ عورتوں کی، بلکہ اقامتِ حدود میں تو صاحبِ حق کو اس کے حق کے دلانے کا تحفظ ہے۔ البتہ خدائی ضوابط کو موردِ طعن ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خالق کے سراپا رحمت نظامِ حیات سے محروم رکھنا یہ خالق اور مخلوق دونوں کی حق تلفی ہے اور دوہرا ظلم ہے۔ اسی لیے ارشادِ ربانی ہے:
ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الظالمون۔ (المائدہ ۴۴)
’’جو خدا تعالیٰ کے نازل کردہ نظامِ حکومت کا نفاذ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔‘‘
کیونکہ خدا تعالٰی کے حقِ اطاعت میں کوتاہی کر کے مخلوق کو اس کی رحمت سے محروم کر کے یہ ظالم اپنی ڈھٹائی سے خدا تعالٰی کے نزدیک فاسق بھی بن جاتے ہیں ’’ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون‘‘ (المائدہ ۴۵)۔ اور شریعت مطہرہ کے نظام کو غیر صالح سمجھ کر منکر ہو جانے پر یہ کافر بھی گردانے جاتے ہیں ’’ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون‘‘ (المائدہ ۴۷)۔
انسان کے وضعی قوانین میں نقص اور خالقِ انسان کے وضع کردہ نظام میں کمال اور جامعیت بالکل اسی طرح بدیہی ہے جیسے کہ خالق و مخلوق میں فرق۔ نہ سمجھیں تو دونوں نظاموں میں تقابل کر لیں۔ بشری قوانین کی قیامِ امن میں عدم صلاحیت جاننے کے لیے اقوامِ عالم میں سب سے ترقی یافتہ ملک امریکہ کو دیکھ لیں کہ اعلیٰ اور جدید ترین مادی وسائل کی کثرت کے باوجود بداَمنی اور اخلاقی گراوٹ میں اسفل سافلین میں ہے۔ عفت و پاکدامنی کا تصور معدوم، دن دہاڑے قتل و غارت اور ڈکیتیاں معمولِ زندگی، کوئی شخص نقدی لے کر جیب میں چلنے کو یوں ہی سمجھتا ہے کہ ایٹم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ جرائم کی کثرت سے مجرموں کے لیے بنائی گئی جیلوں میں گنجائش نہیں تو اب بحری جہازوں میں بند کر کے انہیں کھلے سمندر میں کھڑا کر دیتے ہیں۔
اس کے تقابل میں اسلام کے نظامِ حکومت اور اس کی حدود کے قیام سے پراَمن معاشرے کا صدیوں تک انسانوں نے تجربہ کیا اور آج بھی جن ممالک اسلامیہ میں شرعی سزائیں قائم شدہ کی جاتی ہیں ان میں امنِ عامہ کی حالت مشرق و مغرب میں قابلِ رشک ہے۔ کاش کہ ہم بھی پاکستان میں تنفیذِ شریعت کی عملی مشق کر کے اغیار کے لیے قابلِ تقلید بنتے۔ مگر پاکستانی معاشرے کے بعض افراد جو مادر پدر آزادی کے قائل ہیں اسلامی نظام کے خلاف ہمارے معزز معاشرے کے شرف و کرامت اور عفت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ چاہیئے تو یہ تھا کہ یہ اپنے مغربی آقاؤں کی حالت سے عبرت پکڑتے اور ان کی حالتِ زار پر رحم کے طور پر اور حق نمک خواری کی ادائیگی ان کو اسلام کے جامع نظامِ حکومت کو اختیار کرنے کی دعوت دے کر ان پر احسان کرتے۔ مگر کتنی بے حیائی اور باطل پر ڈھٹائی ہے کہ یہ لوگ الٹا بحالیٔ حقوق کے نام سے شریعتِ مطہرہ کے خلاف ہرزہ سرائی کریں۔ نہ خدا کا خوف مانع ہو نہ مسلم اکثریت کے غیظ و غضب کا ڈر، نہ حکومت کی طرف سے محاسبہ کی فکر۔
حکومت کا فریضہ ہے کہ فکری ارتداد کے حامل، وطن اور ملت کے ان غداروں کا شدید حساب لے، ورنہ پاک وطن کے غیور مسلمان ان کے محلوں، گلی کوچوں، ان کے گھروں اور دفتروں میں ان کا تعاقب کریں گے، پھر اسلام کے فدایان کی گرفت سے مغرب کے ان ایجنٹوں اور قومی ممبروں کو وہ نہ بچا سکیں گے۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’صحبتے با اہلِ حق‘‘
افادات: شیخ الحدیث مولانا عبد الحقؒ
ترتیب و تصنیف: مولانا عبد القیوم حقانی
کتابت و طباعت معیاری۔صفحات ۴۰۶ قیمت مجلد ۷۵ روپے
ناشر: مؤتمر المصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع پشاور
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق نور اللہ مرقدہ کا شمار ہمارے دور کے ان جلیل القدر بزرگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دینی علوم کی ترویج کے میدان میں افادۂ عام کا ذریعہ بنایا اور ملتِ اسلامیہ کے ایک بڑے حصے نے ان سے استفادہ کیا۔ حضرت مولانا عبد الحقؒ کا اٹھنا بیٹھنا اور اوڑھنا بچھونا ہی تعلیم و تبلیغ اور دعوت و ارشاد تھا اور ان کی عام اور نجی مجلسیں بھی علمی استفادہ سے بھرپور ہوتی تھیں۔ مولانا عبد القیوم حقانی نے اپنے شفیق استاذ کی ایسی ہی مجلسوں کے افادات کا احاطہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور ’’صحبتے با اہلِ حق‘‘ کے نام سے حضرت مولانا عبد الحقؒ کے متنوع ارشادات و فیوضات حسنِ ترتیب کے ساتھ جمع کر کے علوم و معارف کا ایک حسین گلدستہ بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں اور علماء اور طلباء کو ان کی اس محنت سے فیضیاب ہونے کی توفیق بخشیں، آمین یا رب العالمین۔
’’کشمیر ۔ بارہ کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ‘‘
تحریر: ریٹائرڈ بریگیڈیر محمد شفیع خان
ناشر: کشمیر اسٹڈیز سنٹر لاہور
صفحات: ۲۴ قیمت دس روپے
ملنے کا پتہ: انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز
کشمیر کا مسئلہ ۱۹۴۷ء سے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازعہ چلا آ رہا ہے اور بھارت اقوامِ متحدہ میں کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کو تسلیم کرنے کے باوجود انہیں عملاً یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بھارت کی اس ہٹ دھرمی کے خلاف کشمیری حریت پسندوں کی جدوجہد مسلسل جاری ہے۔ مسئلہ کشمیر کے ساتھ پاکستانی عوام کی جذباتی وابستگی اظہر من الشمس ہے جس کا متعدد مواقع پر پرجوش اظہار ہوتا رہتا ہے لیکن مسئلہ کشمیر کے تاریخی پس منظر اور اس نازک مسئلہ کے بارے میں حقائق و واقعات سے واقفیت کا رجحان عام نہیں ہے جو ہماری ایک اجتماعی کمزوری ہے۔ جناب محمد شفیع خان نے اپنے اس مضمون کے ذریعے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پائی جانے والی موجودہ بیداری کے ماحول میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی ضرورت ہے۔
’’سیرتِ سیدنا ابوہریرہؓ‘‘
مولف: حافظ محمد اقبال رنگونی
صفحات: ۱۴۴ قیمت ۱۲ روپے
ناشر: دارالمعارف الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور
سیدنا حضرت ابوہریرہؓ تاریخِ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر بیعت کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو ہی اپنا وظیفۂ حیات بنا لیا اور پھر اس ذوق اور محنت کے ساتھ فرموداتِ نبویؐ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا کہ چند سال میں حدیث رسولؐ کے سب سے بڑے راوی کی حیثیت حاصل کر لی۔ حضرت ابوہریرہؓ کی زندگی طلبِ علم اور اشاعتِ دین سے عبارت ہے اور ان کے مجاہدات میدانِ عمل کے راہروؤں کے لیے بلاشبہ سنگِ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اسلامک اکیڈمی مانچسٹر برطانیہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی نے انہی نشانہائے راہ کو اس کتابچہ میں یکجا کیا ہے اور حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے وقیع مقدمہ نے کتابچہ کی اہمیت و افادیت کو دوچند کر دیا ہے۔
’’مسلمان کسے کہتے ہیں؟‘‘
مؤلف: مولانا حافظ مہر محمد
صفحات: ۱۰۰ قیمت ۱۰ روپے
ناشر: جامعۃ العلوم الاسلامیۃ، ایف ٹو، میر پور، آزاد کشمیر
آج کے دور میں اس امر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کے عقائد و اعمال اور اخلاقی احکام و مسائل کو عام فہم انداز میں مختصر طور پر تحریر کیا جائے تاکہ عام پڑھے لکھے لوگ اسلامی احکام و مسائل سے بآسانی واقفیت حاصل کر سکیں۔ مولانا حافظ مہر محمد نے اس ضرورت کے پیشِ نظر یہ رسالہ مرتب کیا ہے جو اپنے مقاصد کے لیے خاصا مفید ہے اور دینی معلومات کو عام لوگوں تک صحیح طور پر پہنچانے کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی ضرورت ہے۔
’’ماہنامہ المذاہب لاہور‘‘
مدیر: جناب محمد اسلم رانا
زرتعاون: سالانہ چالیس روپے
خط و کتابت: ایڈیٹر ماہنامہ المذاہب، ملک پارک، شاہدرہ، لاہور
جناب محمد اسلم رانا کو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے مطالعہ اور تحقیق و تجزیہ کے خصوصی ذوق سے نوازا ہے اور وہ ایک عرصہ سے مختلف جرائد و رسائل کے ذریعے اپنے اس ذوق کا اظہار کرتے آ رہے ہیں اور ان دنوں ماہنامہ ’’المذاہب‘‘ کے نام سے ایک مستقل ماہنامہ کی اشاعت کی ذمہ داری نباہ رہے ہیں۔ عیسائی مشنریاں مختلف عنوانات کے ساتھ اور متنوع پروگراموں کے ذریعے پاکستان کے سادہ لوح عوام کو اپنے جال میں پھنسانے کی جو مسلسل کوشش کر رہی ہیں ان سے عوامی اور دینی حلقوں کی بے خبری بلکہ بے حسی ایک مستقل المیہ ہے جو جناب محمد اسلم رانا کو بے چین کیے ہوئے ہے اور انہوں نے بے سروسامانی کے باوجود اس سلسلہ میں علماء اور عوام کو بیدار کرنے کا مشن سنبھال رکھا ہے۔
’’المذاہب‘‘ کے مضامین علمی اور تحقیقی ذوق کے آئینہ دار اور عیسائیت کے بارے میں معلومات افزا ہوتے ہیں۔ ہم علماء کرام اور طلبہ سے بالخصوص گزارش کریں گے کہ وہ ’’المذاہب‘‘ کے مطالعہ کو معمول بنائیں اور اس مشن میں جناب محمد اسلم رانا کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں۔
قافلۂ معاد
مولانا حق نواز جھنگوی شہیدؒ، مولانا محمد رمضان علویؒ
ادارہ
مولانا حق نواز جھنگوی شہیدؒ
انجمن سپاہِ صحابہؓ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ اور تحفظِ ناموس صحابہؓ کے بے باک نقیب مولانا حق نواز جھنگویؒ ۲۲ فروری ۱۹۹۰ء کو جھنگ صدر میں اپنی رہائش گاہ کے دروازے پر سفاک قاتل کی گولیوں کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا شہیدؒ جامعہ مدنیہ شورکوٹ کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے روانگی کی تیاری کر رہے تھے جہاں انہوں نے رات کی نشست سے خطاب کرنا تھا، اچانک آٹھ بجے کے قریب کسی نے دروازے پر گھنٹی دی، مولانا جھنگویؒ باہر آئے، مبینہ طور پر دو آدمی تھے جن میں سے ایک نے مولاناؒ سے گفتگو شروع کی جبکہ دوسرے نے ریوالور سے پے در پے فائر کر دیے۔ مکان کے سامنے گراؤنڈ میں شادی کی ایک تقریب تھی، انہوں نے شور کوٹ جانے سے قبل اس شادی میں بھی شریک ہونا تھا، فائر کی آواز سے لوگوں نے سمجھا کہ شادی کی خوشی میں نوجوان فائرنگ کر رہے ہیں، یہی اشتباہ حملہ آوروں کے لیے غنیمت ثابت ہوا اور وہ موقع سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگئے۔ گولیاں مولانا جھنگویؒ کے سر، گلے اور پیٹ میں لگیں، وہ وہیں گر گئے۔ انہیں گرتا دیکھ کر اردگرد کے لوگ متوجہ ہوئے، علاقہ میں کہرام مچ گیا، مولانا شہیدؒ کو فورًا ہسپتال لے جایا گیا مگر ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی وہ عروسِ شہادت سے ہمکنار ہوگئے۔
راقم الحروف اس روز شورکوٹ میں تھا، ظہر کے بعد جامعہ مدنیہ شورکوٹ کینٹ میں سالانہ جلسہ سے خطاب کیا اور حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود مدظلہ کے ہمراہ مغرب کی نماز جامعہ عثمانیہ شورکوٹ شہر میں ادا کی۔ نماز کے بعد جامعہ عثمانیہ کے مہتمم مولانا بشیر احمد خاکی کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھے تھے کہ مولانا حق نواز جھنگویؒ کا فون آیا۔ مولانا خاکی کے علاوہ انہوں نے علامہ صاحب اور راقم الحروف سے بھی بات کی۔ کم و بیش سات بجے کا وقت تھا، یہ ہماری آخری گفتگو تھی جو فون پر ہوئی۔ مولانا جھنگویؒ نے جمعیۃ علمائے اسلام پاکستان کے اتحاد اور سنی کاز کی جدوجہد کو سیاسی پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے سلسلہ میں مشاورت کے لیے گوجرانوالہ تشریف آوری کی خواہش کا اظہار کیا اور ہمارے درمیان آئندہ ہفتہ کے دوران کسی وقت مل بیٹھنے کی بات طے ہوئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر علامہ خالد محمود صاحب اور راقم الحروف واپسی کے لیے بس اسٹاپ پر پہنچے تو بہت سے نوجوان سپاہِ صحابہؓ کا پرچم اڑھائے مولانا حق نواز جھنگویؒ کے استقبال کے لیے ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان نوجوانوں نے ہی جھنگ جانے والی ایک ویگن روک کر ہمیں سوار کرایا اور جب ہم جھنگ پہنچے تو یہ روح فرسا خبر اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت ہماری منتظر تھی کہ عزیمت و استقامت کی شاہراہ کا یہ بلند حوصلہ مسافر شہادت کی منزل کو پہنچ چکا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔
نماز جنازہ اگلے روز جمعہ کی نماز کے بعد اسلامیہ ہائی سکول کی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی دامت برکاتہم نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور جھنگ میں کرفیو کے اعلان اور چاروں طرف باہر سے آنے والوں کو روکنے کے لیے پولیس کی ناکہ بندی کے باوجود ملک کے مختلف حصوں سے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق یہ جھنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ نمازِ جنازہ کے بعد مولانا حق نواز جھنگویؒ کے قائم کردہ جامعہ محمودیہ میں انہیں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
جھنگ کے احباب کے مطابق چند روز قبل مولانا جھنگویؒ کو دوبئی سے ایک ٹیلی فون کال کے ذریعہ خبر دی گئی کہ انہیں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور خفیہ ذرائع کے مطابق ۲۰ فروری سے ۲۵ فروری کے درمیان مولانا حق نواز جھنگویؒ، مولانا عبد الستار تونسویؒ اور مولانا منظور احمدؒ چنیوٹی کو قتل کرنے کے ایک منصوبہ کا انکشاف ہوا ہے۔ مولانا جھنگویؒ نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں اس کا ذکر بھی کر دیا اور انتظامیہ کے نوٹس میں بات آگئی لیکن تقدیر کے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے۔
آج مولانا حق نواز جھنگویؒ ہم میں نہیں ہیں، وہ اپنے عظیم مشن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر کے خالقِ حقیقی کے حضور سرخرو ہو چکے ہیں۔ لیکن تحفظِ ناموسِ صحابہؓ کے جس مقدس مشن کی خاطر انہوں نے محنت کی اور قربانی و ایثار کی عظیم روایات کو زندہ کیا وہ مشن زندہ ہے اور جب تک یہ مشن زندہ ہے مولانا حق نواز جھنگویؒ کا نام، خدمت اور قربانی و ایثار کی روایات زندہ رہیں گی۔ ہم اس عظیم سانحہ پر انجمن سپاہِ صحابہؓ کے نوجوانوں، جھنگ کے شہریوں اور مولانا شہیدؒ کے اہلِ خاندان سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا شہیدؒ کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے رفقاء، پسماندگان اور عقیدتمندوں کو صبر و حوصلہ کے ساتھ ان کا مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔
مولانا محمد رمضان علویؒ
گزشتہ دنوں راولپنڈی کے ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد رمضان علویؒ ٹریفک کے حادثہ میں زخمی ہونے کے بعد انتقال فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا علویؒ بھیرہ کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ باپ دادا سے قرآن کریم کی خدمت کا ذوق ورثہ میں ملا تھا۔ ایک عرصہ سے راولپنڈی میں قیام پذیر تھے۔ امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ مجلس احرارِ اسلام میں طویل عرصہ رہے اور جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے ساتھ بھی کچھ عرصہ وابستگی رہی۔ ان دنوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔ خانقاہ سراجیہ شریف کندیاں کے ساتھ روحانی تعلق تھا اور جری، بے باک اور سرگرم عالم دین تھے۔ دینی اور قومی تحریکات میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی وفات سے ہم ایک شفیق، ہمدرد اور دردِ دل سے بہرہ ور مخلص بزرگ اور عالم دین سے محروم ہوگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں اور ان کے فرزندان مولانا عزیز الرحمان خورشید، مولانا سعید الرحمان علوی، دیگر اہل خانہ اور لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔
آپ نے پوچھا
ادارہ
اسلام میں معاشی مساوات کا تصور
سوال: ایک طالب علم تنظیم (۱) خدا پرستی (۲) انسان دوستی اور (۳) معاشی مساوات کو اپنے بنیادی اصول قرار دیتی ہے۔ کیا معاشی مساوات کا تصور اسلام میں ہے؟ (نیاز محمد ناصر بلوچستانی)
جواب: معاشی مساوات کا معنٰی اگر تو یہ ہے کہ ایک معاشرہ کے تمام افراد ایک ہی جیسی زندگی گزاریں اور خوراک، لباس، رہائش، ملکیت، کاروبار اور دیگر معاملات میں ان میں کسی قسم کا کوئی تفاوت اور ترجیحات نہ ہوں تو یہ قطعی طور پر ایک غیر فطری تصور ہے جو نہ صرف یہ کہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے بلکہ عملاً بھی ناممکن ہے۔ ہر انسان ذہنی صلاحیت، قوتِ کار اور وسائل سے استفادہ کی استعداد کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے چار یا پانچ لڑکوں کو ایک ایک ہزار روپے کی رقم دیں اور یہ توقع رکھیں کہ سب کے سب اس رقم کو ایک ہی مدت میں خرچ کریں گے، ایک ہی مصرف میں صرف کریں گے اور ایک ہی جیسے نتائج اور منافع حاصل کریں گے۔ یہ قطعی غیر فطری بات ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اسلام پیداوار کے قومی ذرائع سے استفادہ کا ہر شہری کو یکساں حق دیتا ہے اور قومی ذرائع سے استفادہ کے باب میں ترجیحات کا قائل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شہری اس حق کو استعمال کرنے میں اپنی ذہنی صلاحیت اور قوت کار کے لحاظ سے دوسروں سے بڑھ جائے تو یہ اس کی اپنی محنت اور صلاحیت کا ثمر ہے۔
جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کے دورِ خلافت میں بحرین سے بیت المال میں خاصا سامان اور دولت آئی، اس موقع پر حضرت عمرؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ بیت المال سے وظائف اور اموال کی تقسیم میں ترجیحات قائم کی جائیں اور حضراتِ صحابہؓ کرام میں فضیلت کے جو درجات ہیں اس لحاظ سے تقسیم کے درجات قائم کیے جائیں۔ مثلاً بدری صحابہؓ کو سب سے زیادہ دیا جائے، پھر مہاجرینؓ کو، پھر تیسرے نمبر پر انصارؓ کو اور پھر بعد میں مسلمان ہونے والے حضراتؓ کا درجہ رکھا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے یہ کہہ کر اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ فضیلت کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا ثواب زیادہ یا کم آخرت میں ملے گا ’’وھذہ معاش فالأسوۃ فیہ خیر من الاثرۃ‘‘ اور یہ معیشت ہے اس میں برابری ترجیح سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ اپنے دور خلافت میں اسی اصول پر عمل کرتے رہے لیکن جب حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس اصول کو بدل کر اپنی تجویز کے مطابق ترجیحات کی بنیاد پر وظائف کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا اور دس سالہ دور خلافت میں اسی طریق کار پر عمل کیا۔ البتہ آخری سال انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بیت المال سے وظائف کی تقسیم کے بارے میں حضرت ابوبکرؓ کی رائے درست تھی اس لیے آئندہ سال سے میں موجودہ طریق کار کو ترک کر کے حضرت ابوبکرؓ کے طے کردہ اصول کے مطابق برابری کی بنیاد پر وظائف کی تقسیم کا نظام قائم کروں گا۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمرؓ کی شہادت ہوگئی اور انہیں اپنے نظام پر نظرثانی کا موقع نہیں مل سکا۔
امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں یہ ساری تفصیل بیان کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری اور قومی ذرائع پر تمام شہریوں کا حق یکساں ہے اور اس میں ترجیحات قائم کرنا بہتر نہیں ہے۔ البتہ یہاں زیر بحث مسئلہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز کرنا شاید قرین انصاف نہ ہو۔ وہ یہ کہ صدیقی دور میں بیت المال سے وظائف کی تقسیم برابری کی بنیاد پر ہوتی رہی ہے اور فاروقی دور میں ترجیح کا اصول اپنایا گیا ہے۔ اگرچہ حضرت عمرؓ نے اس سے رجوع کا زبانی اظہار فرما دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ترجیحی اصول پر عملدرآمد کا تسلسل قائم رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دراصل دونوں اصول موقع محل کی مناسبت سے قابل عمل ہیں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی بھی اصول کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اصل بات اجتماعی مفاد کی ہے، اگر کسی وقت حالات کا تقاضا قومی ذرائع پیداوار کی برابری کی بنیاد پر تقسیم کا ہو اور اجتماعی مفاد اس میں ہو تو ایک اسلامی حکومت اس اصول کو اپنا سکتی ہے، اور کسی دور میں اگر اجتماعی حالات کا تقاضا اس کے برعکس ہو تو دوسری صورت اختیار کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔
دینی مدارس کا نصاب اور اکابر کا طرزعمل
سوال: آج مختلف اطراف سے دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی اور اس میں عصری علوم اور تقاضوں کو شامل کرنے کی آواز اٹھ رہی ہے جبکہ ہمارے اکابر نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کسی بزرگ نے اس مقصد کے لیے کوشش کی۔ کیا موجودہ رجحان اکابر کے طرز عمل سے انحراف نہیں ہے؟ (منظور احمد، سمن آباد، گوجرانوالہ)
جواب: یہ کہنا کہ ہمارے اکابر نے دینی مدارس کے نصاب میں عصری تقاضوں کو شامل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی ہے یا اسے پسند نہیں کیا، خلافِ واقعہ بات ہے۔ سب سے پہلے دینی مدارس اور عصری علوم کو اکٹھا کرنے کی بات شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ نے کی تھی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود علی گڑھ تشریف لے گئے تھے۔ ندوۃ العلماء لکھنو کا قیام بھی اسی جذبہ کے تحت عمل میں لایا گیا تھا اور اسی مقصد کے لیے جامعہ ملیہ دہلی کی تشکیل ہوئی تھی۔ اس ضمن میں جمعیۃ العلماء ہند کی مندرجہ ذیل قرارداد بطور خاص اہمیت رکھتی ہے جو جمعیۃ کے تیرہویں عمومی اجلاس منعقدہ لاہور بتاریخ ۲۰ تا ۲۱ مارچ ۱۹۴۲ء میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی زیر صدارت منظور ہوئی تھی۔ قرارداد کا متن یہ ہے:
’’جمعیۃ العلماء ہند کا یہ اجلاس مدارس عربیہ دینیہ کے مروجہ نصاب میں دورِ حاضر کی ضرورتوں کے موافق اصلاح و تبدیلی کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا ہے اور مدارس عربیہ کے ذمہ دار حضرات اور تعلیمی جماعتوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ماہرین تعلیم کی ایک کمیٹی اس پر غور کرنے کے لیے باہمی مشورے اور تعاون سے مقرر کر کے ایک ایسا نصاب مرتب کرائیں جو دینی علوم کی تکمیل کے ساتھ ضروریات عصریہ میں بھی مہارت پیدا کرنے کا کفیل ہو، اور اس سلسلہ میں جمعیۃ العلماء ہند ارباب علم سے رائے لے کر اپنی صوابدید کے مطابق حتی الوسع جلد کوئی مؤثر اقدام کرے۔‘‘
اس سے واضح ہوتا ہے کہ درس نظامی کے نصاب میں عصری تقاضوں کے امتزاج کی ضرورت کا احساس ہمارے اکابر کو بھی تھا، صرف اتنی بات تھی کہ وہ تحریکِ آزادی میں مصروفیات کے باعث اس سمت کوئی نتیجہ خیز عملی پیش رفت نہیں کر سکے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ۱۹۴۲ء میں اس ضرورت کا احساس اس قدر شدت کے ساتھ تھا تو آج ۱۹۹۰ء میں اس کی اہمیت اور ضرورت میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہوگا۔
وعظ و نصیحت کے ضروری آداب
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
(۱) وعظ و نصیحت کا پہلا رکن یہ ہے کہ واعظ سامعین کو ایسے عبرت انگیز واقعات سنائے جن کو سن کر دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجائے، دنیا کی ہوس رانیوں سے دل بیزار ہو جائے، اور توشۂ آخرت جمع کرنے کا خیال دل میں جم جائے، اور نفسانی خواہشات کے درپے رہنے سے دل ہٹ جائے۔ لیکن قصص بیان کرتے وقت یا ترغیب و ترہیب کی روایات سناتے وقت یہ احتیاط رہے کہ کوئی جعلی قصہ یا موضوع روایت ذکر نہ کی جائے جیسے کہ اس عصر کے واعظین کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ہدایت و روشنی کی بجائے گمراہی و تاریکی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب اس انداز سے ہو کہ زمانہ کی گردش کی سرعت اور اس کے ایک نہج پر عدمِ ثبات کو اچھی طرح واضح کرے۔ اس طرح تذکیر و وعظ سے لوگوں کی جبروتی ذہنیت اور سرکشی پاش پاش ہو جاتی ہے۔
(۲) وعظ کا دوسرا رکن یہ ہے کہ واعظ لوگوں کو نظامِ شرعی کی پابندی کے فوائد اور اس کی خلاف ورزی کے مفاسد و نقصانات سمجھائے۔ معاشرتی زندگی میں نظام کے فوائد اور اس کی خلاف ورزی کے مفاسد بیان کرتے وقت ماوراء العقل کلیات بیان کرنے سے گریز کر کے زیادہ تر جزئیات اور فروعی باتوں کا ذکر کرے، اس طرز خطاب کا فائدہ زیادہ حاصل ہو گا۔
(۳) وعظ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ اپنی تقریر و بیان میں دل نشین تشبیہات اور اثر آفرین استعارات اور اصنافِ سخن میں سے مجازات استعمال کرے، اور اپنے بیان میں ایسے بلند و عالی افکار و خیالات کو پیش کرے جو لوگوں کے دلوں کو تسلیم و رضا پر مجبور کریں۔ اسے چاہیئے کہ وہ مسلّمات اور مشہور روایات سے تمسک کرتا رہے۔
لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کو چاہیئے کہ وہ وعظ و تذکیر میں لوگوں کی سطح فہم کے مطابق بات کرے اور کلام کے دقیق و باریک مسائل میں الجھنے سے گریز کرے کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے غلط بیانی سے کام لے گا اور اس سے لوگوں کے اذہان و قلوب منتشر ہوں گے، یا اگر اپنے علم کے مطابق ٹھیک ٹھاک بات کرے گا تو اس کے علم کا فائدہ مخاطبین کو حاصل نہ ہو گا۔ بہرحال یہ مسلّمہ امر ہے کہ وعظ و تذکیر کے سلسلہ میں مؤثر ترین طریقہ اور عوام پر پوری طرح اثر انداز ہونے والا طرز بیان منطقی استدلال نہیں بلکہ خطابیات ہے۔
(البدور البازغہ مترجم (ص ۱۹۳)
قرآنی احکام کا نفاذ آج بھی ممکن ہے
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
خلافت اور رئیس کے باب میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ خلافت تین باتوں کی طرف تقسیم ہوتی ہے:
(۱) خلافت بغیر جماعت کے قائم نہیں ہو سکتی۔
(۲) رئیس صرف اس جماعت میں سے ہو سکتا ہے۔
(۳) رئیس کا انتخاب صرف یہ جماعت کر سکتی ہے۔
براہ راست اس کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ چیز بالآخر نزاع و تنازع و جھگڑا کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ہمارے نزدیک اس معاملے کا صحیح رخ یہ ہے کہ جب اممِ مسلمہ سے کوئی امت یا جماعت ایسے آدمی کو آگے بڑھاتی ہے جو
(۱) کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔
(۲) حضورؐ کے طور طریقوں اور آپؐ کی سنت و تعلیمات کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔
(۳) خلفاء راشدینؓ کے حالات کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔
(۴) ضرورت کے وقت مصلحتِ خاصہ کے مقابلہ میں مصلحتِ عامہ کو ترجیح دینے والا ہو۔ یعنی مصالحِ خاصہ کو مصالحِ عامہ کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ قربان کرنے والا ہو۔
تو ایسا شخص مرکز میں اپنی امت کے لیے نمونہ (نمائندہ) ہو گا۔ اور جب اس قسم کے بہت سے نمائندے مرکز میں جمع ہوں تو ایک اچھی خاصی صالح جماعت مجتمع ہو جائے گی اور اقوام کی اجتماعیت بن جائے گی۔ اور یہ جماعت کتاب اللہ کے اوامر کی تنفیذ کے لیے مسئول ہو گی یعنی قرآن کریم کے قوانین جاری کرنا اس جماعت کی ذمہ داری ہو گی۔
اور قوم اگر ایسی نمائندہ جماعت نہ بنا سکی تو اس کی ایک ذرہ برابر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں، خواہ وہ اپنے ماضی کی تاریخ کے پیشِ نظر ’’پدرم سلطان بود‘‘ کہنے والی ہو، یا اپنی باطل آرزوؤں میں مگن ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی (پاکستانی)، افغانی، تورانی، عربی یہ سب لوگ شرعی سلطنت کو پسند کرتے ہیں لیکن ایسی حکومت تشکیل نہیں کر سکتے۔ باوجودیکہ اوامرِ قرآنیہ کی تنفیذ آج بھی کوشش کرنے پر اممِ مسلمہ سے ممکن ہے، لیکن اگر سعی و کوشش ہی نہ کی جائے تو پھر کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اوامر نافذ ہوں۔ درحقیقت ان اوامر (شرعیہ) کی تنفیذ کے راستہ میں رکاوٹ اور مایوسی اور کوشش نہ کرنا، یہ مستبد سلاطین اور فاجر قسم کے ملوک اور ان کے معاون لوگوں اور عیش پسند علماء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔
(الہام الرحمٰن ۳۰۰ ج ۱)
شہیدِ اسلام مولانا سید شمس الدین شہیدؒ نے فرمایا
ادارہ
’’افسوس کہ آج ہمارا یہ خطہ جس میں مسلمان بستے ہیں اس میں ہمارا قانون، ہمارا آئین اور ہمارا دن بھر کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ وہی ہے جو انگریز ہمارے اوپر مسلط کر گئے تھے۔ ہم آج بھی ان کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ اگر ان کے نقش قدم پر بھی ہم صحیح طور پر چلتے تو آج کچھ نہ کچھ انصاف تو ہم میں ہوتا۔ ہم نے اپنے دین کو ترک کر دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر چلنا ترک کر دیا، اپنے قانون کو ترک کر دیا، ہم نے سب کچھ فراموش کر دیا۔’’
(۱۱ جنوری ۱۹۷۳ء کو بلوچستان اسمبلی سے خطاب)
’’وہ آئین اور دستور اور وہ قانون جو کہ اللہ تبارک و تعالٰی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے مسلمانوں کے فرائض میں ہے کہ سب سے پہلے اس آئین کو دیکھیں اور عمل پیرا ہوں کیونکہ وہ ہمارا حقیقی آئین ہے۔ وہ دستور ہے جو رب العزت کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ مستقل آئین ہے، باقی دنیاوی آئین عارضی اور عبوری ہیں، یہ تو آتے جاتے ہیں۔‘‘
(۱۱ جنوری ۱۹۷۳ء کو بلوچستان اسمبلی سے خطاب)
’’جب دین کے نام پر لیے ہوئے پاکستان میں ہمارے حکمرانوں نے دین کو نافذ نہ کیا۔ اللہ تعالٰی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا اور مسلسل ۲۵ برس تک اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہے، تو پھر قوم و ملک پر اللہ تعالٰی کا عتاب نازل ہوا اور ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ بنگلہ دیش کے نام سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان کا سب کچھ لوٹا یا تباہ و برباد کر دیا۔ اور سب سے بڑی رسوائی یہ ہوئی کہ ہماری فوج نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور نوے ہزار سے زائد سویلین اور فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔ اس کے بعد حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیئے تاکہ دوبارہ ان سابقہ غلطیوں کا اعادہ نہ ہو جن کی وجہ سے ملک و قوم کو یہ دن دیکھنے پڑے۔‘‘
(۱۹ اکتوبر ۱۹۷۳ء کو شیرانوالہ گیٹ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب)
’’ہماری اکثریت کو توڑنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا گیا۔ خود مجھے چیف منسٹری کا عہدہ پیش کیا گیا۔ مگر الحمد للہ میں نے جماعتی منشور، جمہوری اقدار اور اکابر کے ناموس کے پیشِ نظر اس کرسی کو لات مار دی۔ ایک ملاقات میں بھٹو صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، با اصول اور دیانتدار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ میرے ساتھ آئیں اس لیے آپ نیپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے جواب دیا کہ بھٹو صاحب! کیا ہم اقتدار کی خاطر نیپ سے معاہدہ توڑ کر بھی با اصول اور دیانتدار رہیں گے؟ اس پر بھٹو صاحب خاموش ہو گئے۔‘‘
(مدیر ہفت روزہ ترجمان اسلام لاہور سے خصوصی انٹرویو)
’’جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان تعمیر کیا تھا اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا آج وہ مقصد ہم اس ملک میں نہیں چلا رہے بلکہ الٹا اس مقصد اور اس کتاب اور اس اسلام پر وہ مظالم ہم ڈھا رہے ہیں کہ مخالفین اور اسلام اور دین کے دشمنان سے بھی وہ توقع نہیں کی جا سکتی۔‘‘
(شہادت سے چند روز قبل رحیم یار خان میں آخری تقریر)
اپریل ۱۹۹۰ء
اسلامی نظریاتی کونسل کی رجعتِ قہقرٰی
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جس کے قیام کی گنجائش ۱۹۷۳ء کے دستور میں اس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی کہ پاکستان میں مروجہ قوانین کا شرعی نقطۂ نظر سے جائزہ لے کر خلافِ اسلام قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا جائے اور قانون سازی کے اسلامی تقاضوں کے سلسلہ میں قانون ساز اداروں کی راہنمائی کی جائے۔ ۱۹۷۳ء میں دستور کے نفاذ کے موقع پر اس مقصد کے لیے سات سال کی مدت طے کی گئی تھی لیکن ۱۹۷۷ء تک کونسل نے اس سمت کوئی پیشرفت نہ کی تو جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے اپنے دورِ اقتدار میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیلِ نو کر کے اسے نہ صرف متحرک بنایا بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی کی سفارشات کی بنیاد پر حدود آرڈیننس اور دیگر اسلامی قوانین کے نفاذ کا آغاز کیا۔
اس دور میں نافذ ہونے والے اسلامی قوانین کے نامکمل ہونے اور عملدرآمد کا پہلو خاصا کمزور ہونے کے بارے میں دینی حلقے مسلسل آواز اٹھاتے رہے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ چند اسلامی قوانین جس حد تک بھی نافذ ہوئے وہ تمام مکاتب فکر کے سربر آوردہ علماء کرام کی مشاورت اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر تھے اور اصولی اور شرعی لحاظ سے درست تھے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس دور میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی قانون سازی کے حوالے سے ۸۰ فیصد کام مکمل کر کے قوانین کے مسودات مرتب کر دیے تھے جو نفاذ و عملدرآمد کے لیے حکمرانوں کی میز پر تیار پڑے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے موجودہ حکمرانوں کو اسلام کے نفاذ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ ان کی پالیسیوں کا رخ یہ نظر آرہا ہے کہ اسلام کی جدید تعبیر و تشریح اور نام نہاد اجتہاد کے نام پر مغربی افکار و نظریات کو اسلام کے لیبل کے ساتھ مسلط کر دیا جائے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کا ٹھوس علمی و فکری کام ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیلِ نو کر کے اس میں درباری قسم کے نام نہاد علماء اور ملحدین کو شامل کر دیا گیا ہے اور نئی کونسل کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکمران پارٹی کی سربراہ بیگم بے نظیر بھٹو نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ہدایت کی ہے کہ وہ حدود آرڈیننس اور دیگر اسلامی قوانین پر نظرثانی کرے اور انہیں اجتہاد کے نام پر حکمران پارٹی کے مزعومہ رجحانات اور تقاضوں کے مطابق ڈھالے۔
ہمارے نزدیک اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ رجعت قہقرٰی نہ صرف قانون سازی کے اسلامی تقاضوں سے متصادم ہے بلکہ اجتہاد اور تعبیر جدید کے نام پر ملک کو الحاد کی آماجگاہ بنانے کی بھی ایک کوشش ہے جس کا علمی و دینی حلقوں کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔
فضیلۃ الشیخ مولانا محمد مکی حجازی کی تشریف آوری
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کا افتتاح
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی (اٹاوہ، جی ٹی روڈ، گوجرانوالہ) کے ابتدائی بلاک کی تعمیر مکمل ہوگئی ہے۔ یہ بلاک جو عارضی طور پر تعمیر کیا گیا ہے یونیورسٹی کے سائٹ آفس کے علاوہ تعمیری ضرورت کے اسٹورز پر مشتمل ہے اور اس میں پانچ کمرے اور ایک برامدہ شامل ہے، جبکہ پہلے تعلیمی بلاک کی بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی نے سلیم آرکیٹیکٹس لاہور کے ساتھ تعمیر کی نگرانی کے لیے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے اور مذکورہ فرم کی طرف سے یونیورسٹی کا ماسٹر پلان طے کر لیا گیا ہے جس کے مطابق پہلا تعلیمی بلاک اٹھارہ کلاس رومز، اساتذہ کے چودہ کمروں اور دیگر ضروریات پر مشتمل ہوگا جس کی تعمیر کم و بیش ستر لاکھ روپے کی لاگت سے تقریباً ایک سال میں مکمل ہوگی۔
۱۶ مارچ ۱۹۹۰ء کو صبح ساڑھے دس بجے حرم پاک مکہ مکرمہ کے مدرس اور ممتاز عالم دین فضیلۃ الشیخ مولانا محمد مکی حجازی مدظلہ العالی یونیورسٹی کے سائٹ آفس میں تشریف لائے اور ایک سادہ سی تقریب میں دعا کے ساتھ سائٹ آفس کا افتتاح فرمایا۔ اس موقع پر راقم الحروف، الحاج میاں محمد رفیق، میاں محمد عارف ایڈووکیٹ، شیخ محمد یوسف وزیر آبادی، حاجی شیخ محمد یعقوب، ڈاکٹر محمد اقبال لون، مولانا حافظ گلزار احمد آزاد، جناب حاجی علاء الدین، حاجی نذیر احمد، حافظ محمد یحیٰی میر، شیخ محمد ابراہیم طاہر، جناب محمد سلیم (آرکیٹیکٹ)، مولانا قاری حماد اللہ شفیق، مولانا عبد الرؤف ربانی اور دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ مولانا محمد مکی حجازی نے تعلیمی بلاک کی بنیادوں کی کھدائی کا معائنہ کیا اور اس موقع پر اس عظیم تعلیمی منصوبہ کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ انہیں شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا جس پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تعلیمی منصوبہ بہت بڑا ہے جس کی تکمیل کے لیے اَن تھک جدوجہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمی ادارہ امتِ مسلمہ کے ایک بہت بڑے مجدد اور امام کے نام پر قائم کیا جا رہا ہے اور اس کے قیام سے دینی حلقوں میں فکری انقلاب کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے منتظمین کو اس سلسلہ میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔
۱۶ مارچ کو رات ساڑھے آٹھ بجے الحاج میر ریاض انجم کی رہائش گاہ کشمیر ہاؤس ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ میں شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کی مجلس منتظمہ کا ایک اجلاس الحاج میاں محمد رفیق کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں تعمیری پروگرام اور دفتری امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تعمیری کام کی نگرانی کے لیے ایک تعمیراتی کمیٹی قائم کی گئی جس میں میاں محمد عارف ایڈووکیٹ، ڈاکٹر محمد اقبال لون اور حاجی شیخ محمد یعقوب شامل ہیں اور باقی ارکان کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ جبکہ ڈاکٹر محمد اقبال لون کو جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ کا ڈپٹی سیکرٹری منتخب کر کے یونیورسٹی کے دفتری امور کی نگرانی ان کے سپرد کر دی گئی۔
دریں اثنا شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے سربراہ شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر نے اصحابِ ثروت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عظیم تعلیمی و دینی منصوبہ کی تکمیل کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں اور رمضان المبارک کے دوران اس کارِ خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال کر اپنے ذخیرۂ آخرت میں اضافہ کریں۔
ارشاداتِ نبویؐ کی حفاظت کے لیے صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کی خدمات
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کا یہ معمول تھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ جو کچھ سنتے تھے وہ سب لکھ لیتے تھے۔ بعض حضرات صحابہ کرامؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غصہ کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں اور کبھی خوشی کی حالت میں اور تم سب لکھ لیتے ہو؟ حضرت عبد اللہؓ بن عمروؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعت کی۔ آپؐ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بخدا اس سے جو کچھ نکلتا ہے اور جس حالت میں نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے سو تم لکھ لیا کرو۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۸، دارمی ص ۶۷، مسند احمد ج ۲ ص ۴۰۳ و مستدرک ج ۱ ص ۱۰۶)
حضرت عبد اللہؓ بن عمروؓ نے اپنے اس مجموعہ کا نام صادقہ رکھا تھا (طبقات ابن سعدؒ ج ۲ ص ۱۲۵، قسم اول) اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کی آرزو دو چیزوں نے پیدا کر دی ہے جن میں سے ایک صادقہ ہے اور یہ وہ صحیفہ ہے جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر لکھا ہے (مسند دارمی ص ۶۹)۔ اور دوسری چیز دہط نامی زمین تھی جس کو حضرت عمروؓ بن العاص نے وقف کیا تھا اور حضرت عبد اللہؓ اس کے متولی تھے (جامع البیان العلم ج ۱ ص ۷۲)۔ حضرت عبد اللہؓ کا یہی صحیفہ ان کے پوتے عمروؒ بن شعیبؒ کے ہاتھ لگ گیا تھا (ترمذی ج ۱ ص ۴۳ و ج ۱ ص ۸۲) اور یہ اسی صحیفہ سے روایت کرنے کی وجہ سے ضعیف سمجھے جاتے تھے (تہذیب ج ۸ ص ۴۹) کیونکہ حضرات محدثین کرامؒ کے بیان کردہ ضابطہ کے مطابق اگر کسی کو کتاب مل جائے اور صاحبِ کتاب نے اس سے روایت بیان کرنے کی اجازت نہ دی ہو تو اس کتاب سے روایت بیان کرنا حجت نہیں ہے (دیکھئے شرح نخبۃ الفکر ص ۱۰۰ وغیرہ)
حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبد اللہؓ بن عمروؓ کے پاس ایک کتاب دیکھی، ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صادقہ ہے جس میں مندرج روایات کو میں نے براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں ہے (طبقات ابن سعدؒ ج ۲ ص ۱۲۵ قسم اول)۔ حضرت عبد اللہؓ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میں علم کو قیدِ تحریر میں لاؤں؟ آپؐ نے فرمایا، ہاں (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۲ وفیہ عبد اللہؒ بن موملؒ و ثقہ ابن معینؒ و ابن حبانؒ و قال ابن سعدؒ و قال الامام احمدؒ احادیثہ مناکیر و جامع بیان العلم ج ۲ ص ۲۷)
حضرت عائشہؓ (المتوفاۃ ۵۷ھ) فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے سے دو تحریریں دستیاب ہوئیں جن میں درج تھا کہ سب سے بڑا نافرمان وہ شخص ہے جس نے اپنے پیٹنے والے کے علاوہ کسی اور کو پیٹا اور قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کو قتل کیا، اور وہ شخص جس نے اپنی پرورش کرنے والوں کے علاوہ دوسروں سے اپنا الحاق کر لیا اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا منکر ہے اور اس کی کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہ ہو گی (مستدرک ج ۴ ص ۳۴۹ قال الحاکمؒ و الذہبیؒ صحیح)
حضرت نہثلؓ بن مالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین کی کچھ باتیں دریافت کیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ بن عفان کو حکم دیا ’’فکتب لہ کتابا فیہ شرائع الاسلام‘‘ (البدایۃ والنہایۃ ج ۵ ص ۳۵۱ اور تجرید ج ۲ ص ۱۲۲ للذہبیؒ میں بھی اس کتاب کا ذکر ہے) تو انہوں نے ان کو ایک کتاب لکھ کر دی جس میں اسلام کے احکام تھے۔ شرائع الاسلام کا جملہ بڑا واضح اور وسیع ہے۔
مردم شماری
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو چھ اور سات سو کے درمیان نام قلمبند ہوئے (صحیح ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۰۲) اور اس کے بعد ایک موقع پر مردم شماری کرائی گئی تو تعداد پندرہ سو تحریر ہوئی (بخاری ج ۱ ص ۴۲۰) اور اس میں آپؐ کے یہ الفاظ ہیں ’’اکتبوا لی من یلفظ بالاسلام من الناس فکتبنا لہ‘‘ (الحدیث) یعنی مجھے مسلمانوں کی گنتی لکھ کر دو چنانچہ ہم نے لکھ کر دی۔
زکوٰۃ کے متعلق تحریرات
زکوٰۃ کے احکام اور مختلف چیزوں میں زکوٰۃ کا لازم ہونا اور زکوٰۃ کی مختلف شرح کتابی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی جو حضرت عمرؓ کے خاندان کے پاس تھی (ہذہ نسخۃ کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم التی کتب فی الصدقہ وھو عند آل عمرؓ بن الخطاب الخ (دارقطنی ج ۱ ص ۲۰۹) اور یہ کتاب حضرت عمرؒ بن عبد العزیزؒ نے جب کہ وہ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے حضرت عبد اللہؒ بن عبد اللہؓ بن عمرؓ اور حضرت سالمؒ بن عبد اللہؓ سے نقل کی تھی اور اپنے ماتحت افسروں کو حکم دیا تھا کہ اسی کتاب کے مطابق عمل کرو اور اسی کے مطابق خلیفہ ولید بن عبد المالک اور دیگر خلفاء عمل کرتے اور حکام سے زکوٰۃ کے بارے میں عمل کرواتے تھے (دارقطنی ج ۱ ص ۲۰۹) اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیز (المتوفی ۱۰۱ھ) جب خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے
ارسل الی المدینۃ یلتمس عھد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الصدقات فوجد عند آل عمروؓ بن حزم کتاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الیٰ عمرو بن حزم فی الصدقات ووجد عند آل عمرؓ بن الخطاب کتاب عمرؓ الیٰ عمالہ فی الصدقات بمثل کتاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی عمروؓ بن حزم فامر عمرؓ بن عبد العزیزؓ عمالہ علی الصدقات ان یاخذوا بما فی ذینک الکتابین۔
’’مدینہ طیبہ قاصد بھیجا تاکہ وہ اس تاکیدی فرمان کی تلاش کرے جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقات کے بارے میں فرمایا تھا۔ چنانچہ قاصد نے حضرت عمروؓ بن حزم کے خاندان کے پاس وہ کتاب پائی جو صدقات کے بارے میں آپؐ نے جاری فرمائی تھی اور اسی طرح حضرت عمرؓ کے خاندان کے پاس بھی وہ تحریر پائی جو انہوں نے عمّال کو بھیجی تھی اور وہ کتاب اسی طرح کی تھی جس طرح کی کتاب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمروؓ بن حزم کو ارسال کی تھی۔ حضرت عمرؒ بن عبد العزیزؒ نے اپنے عمّال کو انہی دو کتابوں کے بارے تاکید کی کہ وہ صدقات کے بارے انہی کتابوں پر عمل کریں۔‘‘
حضرت عمروؓ بن حزم کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر ان کو لکھوا کر دی جس میں فرائض صدقات اور دیات وغیرہا کے متعلق بہت سی ہدایات تھیں (نسائی ج ۲ ص ۲۱۸ و کنز العمال ج ۳ ص ۱۸۳) اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بعض دیگر محصلین کے پاس بھی تحریری ہدایتیں موجود تھیں (دارقطنی ج ۱ ص ۲۰۴)
صحیفۃ علیؓ
حضرت علیؓ (المتوفی ۳۰ھ) کے پاس ایک صحیفہ تھا جو ان کی تلوار کی نیام میں پڑا رہتا تھا۔ اس میں متعدد حدیثیں متعلقہ احکام قلم بند تھیں اور انہوں نے لوگوں کو وہ صحیفہ دکھایا بھی تھا (بخاری ج ۲ ص ۱۰۸۴، مسلم ج ۲ ص ۱۶۱، ادب المفرد ص ۵) اور اس صحیفہ میں متعدد احکام درج تھے جو حقوق اللہ و حقوق العباد پر مشتمل ہیں (دیکھئے بخاری و مسلم صفحات مذکورہ)۔ اور حضرت علیؓ نے ایک موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ صحیفہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے۔ اس میں فرائض صدقات ہیں (مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۹)۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ حضرت علیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا تھا اس کی ایک نقل قریش نے لی اور ایک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھی (طبقات ابن سعدؒ مغازی ص ۷۱)۔ حضرت علیؓ کے فیصلوں کا ایک بڑا حصہ کتابی شکل میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس موجود تھا (مسلم ج ۱ ص ۱۰)۔ ایک دن کوفہ میں حضرت علیؓ خطبہ دے رہے تھے، اسی خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ ایک درہم میں کون علم خریدنا چاہتا ہے؟ حارث اعور ایک درہم کے کاغذ خرید لائے اور ان کاغذوں کو لیے ہوئے حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علیؓ نے حارث کے لائے ہوئے اوراق میں ’’فکتب لہ علمًا کثیرًا‘‘ (طبقات ابن سعدؒ ج ۶ ص ۱۱۶) انہیں بہت سا علم لکھ دیا۔
حضرت عبد اللہؓ بن الحکیم کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پہنچا جس میں مردہ جانور کے متعلق حکم درج تھا (معجم صغیر طبرانیؒ ص ۳۱۷)۔ حضرت وائلؓ بن حجر جب بارگاہِ نبویؐ سے رخصت ہو کر اپنے وطن حضرموت جانے لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر ایک نامہ لکھوا کر دیا جس میں نماز، روزہ، ربوا، شراب اور دیگر امور کے متعلق احکام تھے (معجم طبرانیؒ ص ۲۴۲)۔ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے مجمع سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی دیت میں سے بیوی کو کیا دلایا؟ تو حضرت ضحاکؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں لکھوا کر بھیجا تھا (دارقطنی ج ۲ ص ۴۵۷) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو تحریر کروا کر بھیجنے کا ذکر ابوداؤد ج ۲ ص ۵۰، ترمذی ج ۲ ص ۳۲ اور ابن ماجہ ص ۱۹۳ وغیرہ) میں بھی ہے۔یہودِ مدینہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری معاہدہ کیا تھا اس کا ذکر ابوداؤد ج ۲ ص ۶۶ وغیرہ میں مذکور ہے۔
حضرت عمرؓ (المتوفی ۲۳ھ) کا یہ عام ارشاد تھا کہ علم کو قیدِ تحریر میں لاؤ (مستدرک ص ۱۰۶)۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عتبہؓ بن فرقد کو جب کہ وہ آذربائیجان کے محاذ پر تھے، یہ خط لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے سے منع کیا ہے، ہاں مگر چار انگشت تک کا حاشیہ اور کنارہ ہو تو گنجائش ہے (محصلہ مسلم ج ۲ص ۱۹۱)
حضرت انسؓ (المتوفی ۹۳ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عتبانؓ سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی جس میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سچے دل سے کلمۂ شہادت پڑھا تو اس پر آتشِ دوزخ حرام ہے (یعنی صدقِ دل سے پڑھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا) مجھے یہ حدیث بہت پسند آئی اور میں نے لکھ لی (ابوعوانہ ج ۱ ص ۱۳)۔ حضرت انسؓ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ علم کو قیدِ تحریر میں لاؤ (تلخیص المستدرک ج ۱ ص ۱۰۶ و دارمی ص ۶۸ طبع ہند و ص ۱۲۷ طبع دمشق و مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۲ رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ رجال الصحیح)
حضرت عبد اللہ بن عمروؓ (المتوفی ۷۴ھ) نے بھی فرمایا کہ علم کو قیدِ تحریر میں لاؤ (دارمی) اور خود انہوں نے ایک شخص کو حدیث لکھوائی اور اس نے لکھ لی (مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۹)۔ اور حضرت ابن عمرؓ مجوزین کتابِ علم میں شامل ہیں (بخاری ج ۱ ص ۱۵)۔ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت عائشہؓ کو خط لکھا کہ مجھے مختصر طور پر چند نصائح لکھ کر بھیجیں۔ حضرت عائشہؓ نے چند نصیحتیں ان کو لکھ کر روانہ کیں (ترمذی ج ۲ ص ۶۴)۔ حضرت جابرؓ کی روایتوں کا ایک مجموعہ حضرت وہب تابعیؒ نے تیار کیا تھا جو اسمٰعیلؒ بن عبد الکریمؒ کے پاس تھا اور وہ اس سے روایت بیان کرتے تھے اور اسی لیے ضعیف سمجھے جاتے تھے (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۱۶)۔ حضرات محدثین کرامؒ کا ضابطہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت جابرؓ کی روایتوں کا ایک مجموعہ حضرت سلیمانؒ بن قیس یشکریؒ نے تیار کیا تھا۔ حضرت ابو الزبیرؒ، حضرت ابو سفیانؒ اور حضرت شعبیؒ جو سب تابعی ہیں حضرت جابرؓ کا صحیفہ انہیں سے روایت کرتے ہیں اور براہِ راست بھی انہوں نے حضرت جابرؓ سے سماعت کی ہے (تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۲۱۵)
حضرت عوفؓ بن مالک (المتوفی ۷۳ھ) فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا ’’ھذا اوان رفع العلم‘‘ یعنی کشفی طور پر جو وقت نظر آ رہا ہے اس میں علم اٹھ جائے گا۔ ایک انصاری نے کہا جن کا نام زیادؓ بن لبید (المتوفی ۴ھ) تھا، یا رسول اللہؐ! علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ’’وقد اثبت فی الکتب و رعتہ القلوب‘‘ جب کہ وہ کتابوں میں ثبت کیا گیا ہو گا اور دلوں نے اس کو یاد کیا ہو گا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا علم یہود اور نصارٰی کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے؟ (الحدیث) (مستدرک ج ۱ ص ۹۹ قال الحاکمؒ والذہبیؒ صحیح و مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۰۰)۔ مطلب واضح ہے کہ علم صرف لکھنے اور یاد کرنے ہی سے باقی نہیں رہتا جب تک کہ اس پر عمل بھی نہ ہو اور اس کی عام اشاعت نہ ہو۔ آخر کتابیں تو یہود و نصارٰی کے پاس بھی تھیں لیکن علماء حق کے اٹھ جانے اور بے عملی اور کتب پر علماء سوء اور پیرانِ بدکردار کی اجارہ داری نے کتب میں درج شدہ علم کی روح ختم کر دی ہے۔ حضرت زیادؓ کی یہ روایت مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۸ میں بھی بحوالہ مسند احمد و ابن ماجہ و ترمذی و دارمی نقل کی گئی ہے اور یہ روایت مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۰۰ میں بھی ہے۔ مشکوٰۃ کی روایت میں یہود و نصارٰی کی بے عملی اور تورات و انجیل کا ذکر ہے اور مجمع الزوائد کی روایت میں تورات و انجیل اور یہود و نصارٰی کا تذکرہ ہے لیکن اس میں رفع العلم کا سبب حاملینِ علم کا اٹھ جانا مذکور ہے۔ اور حضرت زیادؓ کی ایک اور روایت ہے جس میں یہود و نصارٰی کے تورات و انجیل پر عمل نہ کرنے کا ذکر ہے (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۰۱ و اسنادہ حسن) اور اسی مضمون کی ایک روایت حضرت ابوالدرداءؓ سے بھی ہے جس میں حضرت زیادؓ کے سوال کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا تذکرہ موجود ہے کہ یہود و نصارٰی کے پاس بھی تورات و انجیل موجود ہیں ’’فماذا یعنی عنھم‘‘ یعنی ان کے مطابق عقیدہ اور عمل اور اخلاق کے نہ ہونے سے محض کتابوں کے موجود ہونے سے کیا فائدہ؟
یعنی یہ تو ’’تحمل اسفارًا‘‘ کا مصداق ہے۔ اس مفصل روایت کی روشنی میں یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ جب حضرت زیادؓ نے یہ فرمایا کہ ’’وقد اثبت فی الکتب‘‘ کہ علم جب کتابوں میں لکھا اور درج کیا ہوا ہو گا تو پھر کیسے ضائع ہو گا؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اگر علم لکھنا ممنوع ہوتا تو آپؐ اس پر ہرگز خاموشی اختیار نہ فرماتے بلکہ سختی سے تردید فرما دیتے کہ علم کو لکھنے کا کیا جواز ہے؟ اور اگر کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے تو اسے مٹا دے۔ بالکل ظاہر امر ہے کہ آپؐ کا اس پر سکوت فرمایا بلکہ صاف الفاظ میں یہ فرمانا کہ آخر تورات و زبور بھی تو لکھی ہوئی ہیں لیکن ان پر عمل کیے بغیر نرے لکھنے سے کیا فائدہ؟ کتابتِ علم کے جواز کی یہ بھی واضح دلیل ہے اور بقول مولانا رومؒ علم تو صرف
؏ علمِ دیں فقہ است و تفسیر و حدیث
ہے اور یہ علوم سرِ فہرست کتابوں میں لکھے جاتے ہیں۔ حضرت زیادؓ بن لبید بیاضی کو جب آنحضرتؐ نے حضرموت کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو فرائضِ صدقات کے متعلق کتابی ٍشکل میں تحریر لکھوا کر دی (نصب الرایۃ ج ۳ ص ۴۵۱)۔ حضرت براء بن عازبؓ (المتوفی ۷۲ھ) کے پاس لوگ بیٹھ کر ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی ص ۶۹)۔ اہلِ یمن کو آنحضرتؐ نے جو احکام لکھوا کر بھجوائے تھے ان میں یہ مسئلے بھی تھے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگایا جائے اور غلام خریدنے سے پہلے آزاد نہیں کیا جا سکتا اور نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی (دارمی ص ۲۹۳) اور اس کتاب کا اور بغیر طہارت کے قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگانے کا ذکر دارقطنی ج ۱ ص ۴۵ وغیرہ میں بھی ہے۔ حضرت رافعؓ بن خدیج (المتوفی ۷۳ھ) مروان نے اپنے خطبہ میں یہ بیان کیا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے۔ حضرت رافعؓ بن خدیج نے بلند آواز سے پکار کر فرمایا کہ مدینہ طیبہ بھی حرم (اور عزت و احترام کا مقام) ہے اور یہ حکم میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اسے پڑھ کر سنا دوں (مسند احمد ج ۴ ص ۱۴۱)۔ حضرت نعمانؓ بن بشیرؓ (المتوفی ۶۴ھ) کو حضرت ضحاکؓ بن قیس نے خط لکھ کر دریافت کیا کہ آنحضرتؐ جمعہ کی نماز میں سورۂ جمعہ کے بغیر اور کون سی صورت پڑھتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ’’ھل اتاک حدیث الغاشیۃ‘‘ پڑھتے تھے (مسلم ج ۱ ص ۲۸۸)
حضرت عبد اللہؓ بن عباسؓ کی روایتوں کے مختلف تحریری مجموعے تھے۔ اہلِ طائف میں سے کچھ لوگ ان کا ایک مجموعہ ان کو پڑھ کر سنانے کے لیے لائے تھے (کتاب العلل امام ترمذیؒ ص ۲۳۸) حضرت سعیدؒ بن جبیرؒ ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی ص ۶۹)۔ امام مغازی حضرت موسؒیٰ بن عقبہؒ (المتوفی ۱۴۱ھ) فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابن عباسؓ کے غلام حضرت کریبؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی کتابیں رکھوائی تھیں جو ایک بارشتر تھیں (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۴۳۳)۔ حضرت ابن عباسؓ کا یہ حال تھا کہ وہ آنحضرتؐ کے غلام حضرت ابو رافعؓ کے پاس آتے اور سوال کرتے کہ فلاں دن آنحضرتؐ نے کیا کیا؟ اور حضرت ابن عباسؓ کے ساتھ ایک شخص ہوتا جو ان کی ساری باتوں کو جنہیں حضرت ابو رافع بیان کرتے لکھتا جاتا (الکتانی ج ۲ ص ۲۴۷)۔ حضرت ابو رافعؓ کی اہلیہ حضرت سلمٰیؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو دیکھا کہ ان کے پاس تختیاں تھیں جن پر حضرت ابو رافعؓ کی بیان کردہ روایتوں کو وہ لکھا کرتے تھے جو آنحضرتؐ کے افعال کے متعلق حضرت ابو رافعؓ بیان کرتے تھے (الکتانی ج ۲ص ۲۴۷) اور حضرت سلمٰیؓ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو رافعؓ سے آنحضرتؐ کے کارنامے لکھا کرتے تھے (طبقات ابن سعدؒ ج ۲ ص ۱۲۳ قسم دوم)۔
حضرت عکرمہؒ (المتوفی ۱۰۷ھ) فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے جو خط (بحرین کے سربراہ) المنذر بن ساوٰی کو بھیجا تھا وہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کی وفات کے بعد ان کی کتابوں میں پایا اور میں نے وہ لکھ لیا اور اس خط میں دینی اور ملکی باتوں کا ذکر ہے (زاد المعاد ج ۳ ص ۶۱)۔ اس کے علاوہ متعدد بادشاہوں اور اپنے اپنے علاقہ کے سربراہوں کو آنحضرتؐ نے جو خطوط ارسال کیے جن میں دین کا اہم ذخیرہ موجود ہے کتب سیر و تاریخ میں ان کی خاصی تفصیل موجود ہے۔ ان میں مصر کا بادشاہ مقوقس، عمان کا بادشاہ جیفر بن الجلندی، یمامہ کا ہوذہ بن علی، غسان کا حارث بن ابی ثمر خاصے مشہور و معروف ہیں۔ حافظ ابن القیمؒ (المتوفی ۷۵۱ھ) نے زاد المعاد ج ۳ ص ۶۰ تا ۶۳ میں ان کو قدرے تفصیل سے درج کیا ہے اور آپؐ کے ارسال کردہ ان خطوط اور دعوت ناموں کے سلسلہ میں حضرت مولانا محمد حفظ الرحمٰن صاحب سیوہارویؒ کی بے نظیر کتاب البلاغ المبین فی مکاتیب سید المرسلین (علیہ و علیٰ جمیعھم الصلوٰۃ والتسلیمات الف الف مرتٍ) مفید ترین کتاب ہے جو اہلِ علم کے لیے ایک علمی تحفہ ہے جس میں ان خطوط کی پوری تفصیل ہے۔ حضرت کریبؒ (المتوفی ۹۸ھ) فرماتے ہیں کہ چھ باتیں میرے تابوت میں لکھی ہوئی ہیں اور تابوت (وہ صندوق ہے جس) میں حضرت علیؒ بن عبد اللہؓ بن عباسؓ کی کتابیں تھیں (ابوعوانہ ج ۲ ص ۲۱۲)
حضرت امیر معاویہؓ (المتوفی ۶۰ھ) نے حضرت مغیرہؓ کو لکھا کہ وہ دعا (اکثر) آنحضرتؐ نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے مجھے لکھ کر بھیجو تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ آنحضرتؐ یہ دعا پڑھتے تھے:
لا الٰہ الا اللہ وحدہٗ لا شریک لہٗ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قدیر ۔ اَللّٰھُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَلَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا یَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْکَ الْجَدّ (ابوعوانہ ج ۲ ص ۲۴۳ وابوداؤد ج ۱ ص ۲۱۱، ادب المفرد ص ۶۷)
اور اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی لکھ کر بھیجا کہ آنحضرتؐ نے قیل و قال کثرت سوال اضاعتِ مال اور ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور خود نہ دینے اور دوسروں سے مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ (ادب المفرد ص ۶۷ و بعضہ فی ص ۵ اور ان میں سے بعض چیزوں کے لکھ کر ارسال کرنے کا ذکر بخاری ج ۱ ص ۲۰۰ میں بھی ہے اور قدرے تفصیل سے بعض مزید چیزوں کا ذکر بخاری ج ۲ ص ۸۸۴ میں ہے)۔ حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت عبد الرحمٰن بن شبل الانصاریؓ کو خط لکھ کر بھیجا کہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دو اور جب میرے خیمے کے پاس کھڑے ہو تو مجھے حدیثیں سناؤ (مسند احمد ج ۳ ص ۴۴۴)۔ یہ سننا سنانا شاید اس لیے تھا کہ کہیں ان سے حدیث میں غلطی تو نہیں ہوتی۔
حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے آنحضرتؐ سے شکایت کی کہ میں بسا اوقات آپؐ سے کوئی حدیث سنتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتی ہے لیکن میں اس کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو (رحمۃ مہداۃ ص ۱۱)۔ حضرت عبد اللہؓ نے حضرت عمرؓ بن عبد اللہ بن ارقم الزہریؓ کو خط لکھا کہ حضرت سبیعہؓ بنت الحارث الاسلمیۃ کے پاس جاؤ اور ان سے (خاوند کی وفات کے بعد عورت کی عدت کے بارے) حدیث دریافت کرو اور ان کو آنحضرتؐ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بھی دریافت کرو۔ چنانچہ ان سے دریافت کرنے کے بعد وہ حدیث انہیں تحریر کر کے انہوں نے بھیجی (نسائی ج ۲ ص ۹۸)
حضرت عبد اللہؓ بن عمروؓ بن العاص کے سامنے قسطنطنیہ اور رومیہ کی فتح کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق طلب کیا، اسے کھولا اور فرمایا کہ ہم آنحضرتؐ کے پاس تھے اور آپؐ کے ارشادات لکھتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہو گا (مستدرک ج ۴ ص ۴۲۲ قال الحاکمؒ والذہبی صحیح والدارمی ص ۶۸)۔ حضرت حجرؒ بن عدیؓ کے سامنے پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ طاق میں جو صحیفہ رکھا ہوا ہے ذرا اسے مجھے لا کر دو۔ جب وہ صحیفہ لا کر دیا گیا تو حجرؒ بن عدیؓ یہ پڑھنے لگے ’’بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو میں نے حضرت علیؓ بن ابی طالب سے سنی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ طہور ایمان کا نصف ہے‘‘ (طبقات ابن سعدؒ ج ۶ ص ۱۵۴)۔ ایمانِ کامل طہارتِ باطنی (جو کلمۂ توحید سے حاصل ہوتی ہے) اور طہارتِ ظاہری (جو وضو وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے) کا نام ہے۔
محدث عبد الاعلٰیؒ (المتوفی ۵۱ھ) جو روایتیں حضرت محمدؒ بن الحنیفیہؒ سے نقل کرتے تھے وہ دراصل ایک کتاب تھی اور عبد الاعلٰیؒ نے براہِ راست وہ روایتیں حضرت محمدؒ بن الحنیفیہؒ سے نہیں سنی تھیں (طبقات ابن سعدؒ ج ۶ ص ۹۴)۔ امام جعفر صادقؒ (المتوفی ۱۴۸ھ) فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو روایتیں اپنے آباؤاجداد سے نقل کرتے ہیں میں نے ان سب کو حضرت امام باقرؒ کی کتابوں میں پایا ہے (تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۰۴)۔ حضرت سمرہؓ بن جندب (المتوفی ۵۹ھ) سے ان کے بیٹے حضرت سلیمانؒ روایتوں کا ایک نسخہ روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے بیٹے حضرت حبیبؒ (تہذیب ج ۴ ص ۲۳۶)۔ اور حضرت محمدؒ بن سیرینؒ فرماتے ہیں ’’فی رسالۃ سمرۃؓ الٰی بنیہ علم کثیر‘‘ (ایضًا) یعنی اس رسالہ اور تحریر میں جو حضرت سمرۃؓ نے اپنے بیٹوں کو بھیجی بہت بڑا علم ہے۔
مشہور تابعی حضرت ابو سبرۃؒ بن سلمۃ الہذلؒ (جو تابعی کبیر تھے مستدرک ج ۱ ص ۷۶ و سکت عنہ الذہبیؒ) فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہؓ بن عمروؓ سے ملا۔ انہوں نے زبانی مجھ سے حدیث بیان کی اور میں نے اپنے قلم سے اسے لکھا اور اس میں ایک حرف کی کمی بیشی میں نے نہیں کی۔ اس حدیث میں بہت سی باتوں کا ذکر ہے جن میں سے بعض یہ بھی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہو گی جب تک کہ فحش گوئی اور بدکلامی اور قطع رحمی اور پڑوس کے حقوق کو پامال کرنا اور امانت والے کا خیانت کرنا اور خائن کو امین تصور کرنا وغیرہ امور ظاہر نہ ہو جائیں (الحدیث) (مستدرک ج ۱ ص ۷۵ امام حاکمؒ اور علامہ ذہبیؒ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی مروی ہے۔ تلخیص المستدرک ج ۱ ص ۷۶)
حضرت عروہؒ بن الزبیرؓ (المتوفی ۹۴ھ) نے غزوۂ بدر کا مفصل حال لکھ کر خلیفہ عبد الملک کو بھیجا تھا (طبری ص ۱۲۸۵)۔ حضرت سعیدؒ بن جبیرؒ (المتوفی ۹۵ھ) فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے رات کو روایتیں سنتا تھا تو پالان پر لکھتا تھا صبح کو پھر ان کو صاف کر کے لکھ لیتا تھا (دارمی ص ۶۹)۔ حضرت نافعؒ (المتوفی ۱۱۷ھ) جو حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں تیس برس رہے تھے وہ اپنے سامنے لوگوں کو لکھوایا کرتے تھے (دارمی ص ۶۹)۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عبد اللہؓ بن مسعود (المتوفی ۷۹ھ) ایک کتاب نکال لائے اور قسم کھا کر کہا کہ یہ کتاب خود حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷۲)۔ قاضی ابن شبرمہؒ (عبد اللہؒ بن شبرمہؓ المتوفی ۱۴۴ھ) سے بعض امراء نے سوال کیا کہ یہ حدیثیں جو آپ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتے ہیں یہ کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کتاب عندنا (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷۶) کہ یہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں۔
حضرت امام زہریؒ (المتوفی ۱۲۴ھ) محدث ابوالزناؤؒ فرماتے ہیں کہ ہم تو صرف حلال و حرام کے مسائل ہی لکھتے رہتے تھے لیکن امام زہریؒ جو کچھ سنتے وہ سب لکھ لیتے تھے اور بعد کو جب مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کی حاجت پڑی تو میں نے اس وقت یہ جانا کہ وہ اعلم الناس ہیں (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷۳)۔ محدث کیسانؒ کا بیان ہے کہ میں اور امام زہریؒ طلبِ علم میں ایک ساتھ تھے۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف سنن ہی لکھوں گا۔ چنانچہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھا وہ میں نے سب لکھ لیا اور امام زہریؒ نے کہا کہ حضرات صحابہ کرامؓ سے جو کچھ مروی ہے وہ بھی لکھو کیونکہ وہ بھی سنت ہی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ سنت نہیں۔ غرضیکہ میں نے وہ نہ لکھا اور امام زہریؒ نے وہ بھی لکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوئے اور میں برباد ہو گیا (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۸۷ و طبقات ابن سعدؒ ج ۲ ص ۱۳۵ قسم دوم)۔ امام زہریؒ ہی وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے علم کی تدوین کی اور اس کو لکھا (جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷۳)۔
قارئین کرام! آپ ان ٹھوس حوالوں سے بخوبی یہ معلوم کر چکے ہیں کہ علم اور حدیث کی کتابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؒ کے مبارک دور میں باقاعدہ ہوتی تھی، ہاں مگر مرتب نہ تھی۔ ابواب اور فصول وغیرہا کی صورت میں فقہی رنگ میں تدوین سب سے پہلے حضرت امام زہریؒ نے کی ہے تاکہ مسائل اور احکام کو تلاش کرنے میں بھی کوئی دقت پیش نہ آئے اور اہم سو اہم کی ترتیب بھی برقرار رہے جیسا کہ پہلے باحوالہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے۔
بعد کے لوگوں میں حفظِ حدیث اور عمل کے جذبہ میں بہ نسبت پہلے مبارک دور کے جب کچھ کمی نظر آنے لگی تو خلیفہ راشد حضرت عمرؒ بن عبد العزیزؒ نے اپنے قابل اور فاضل گورنر حضرت ابوبکرؒ بن حزم کو سرکاری سطح پر حکم لکھ کر بھیجا کہ بغور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کر کے لکھو کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے اٹھ جانے کا خطرہ ہے اور صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی لکھنا اور اہلِ علم کو چاہیئے کہ علم کی خوب اشاعت کریں اور علمی مجالس میں بیٹھ کر تعلیم دیں تاکہ جن کو علم نہیں وہ علم حاصل کریں۔ علم صرف اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب کہ وہ راز بن جائے (اور اس کی نشرواشاعت نہ کی جائے) (بخاری ج ۱ ص ۲۰ و رحمۃ مہداۃ ص ۱۱) اسی طرح حضرت عمرؒ بن عبد العزیزؒ نے اہل مدینہ کو تحریر فرمایا کہ
ان انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاکتبوہ فانی خفت دروس العلم و ذھاب اھلہ (دارمی ص ۶۸)
’’توجہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھو کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور اہلِ علم کے اٹھ جانے کا خدشہ ہے۔‘‘
خیر القرون کے ذمہ دار اور باشعور حضرات نے تو ازخود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت اور محبت کی بنا پر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے پوری ذمہ داری محسوس کی اور حفظ و کتابت حدیث کا پورا پورا ثبوت دیا لیکن خلیفۂ راشد اور پہلی صدی کے مجدد حضرت عمرؒ بن عبد العزیزؒ نے سرکاری طور پر جس ذمہ داری کا ثبوت دیا وہ ان کا خالص مجددانہ کارنامہ ہے۔
غرضیکہ یہ ٹھوس حوالے اس بات کو بالکل واضح کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ اور حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ اور تبع تابعینؒ کے زمانہ میں جہاں احادیث کے نوکِ زبان کرنے کا عام رواج اور شوق تھا وہاں کتابتِ حدیث کی بھی کمی نہ تھی گو ان حضرات کے مجموعے فقہی ابواب پر مدوّن اور مرتب نہ تھے لیکن ان میں علمی طور پر بہت کچھ درج تھا اور اس دور میں بھی باقاعدہ حدیثیں اور روایتیں قیدِ تحریر میں لائی جاتی تھیں اور وہی قیمتی ذخیرہ سینوں اور سفینوں میں منتقل ہوتا ہوا نچلے روات اور محدثین تک پہنچا۔
گویا دورِ اول کا سرمایۂ حدیث دوسرے دور کی کتابوں میں ہے۔ اور دوسرے دور کا تحقیقی مواد تیسرے دور کی کتابوں کی زینت ہے۔ اور تیسرے دور کی کتابوں میں جو اول اور دوسرے دور کی کتابیں کھپا دی گئی تھیں وہ ہزاروں اوراق میں فقہی ترتیب اور تدوین کے ساتھ ہمارے سامنے مؤطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابی ماجہ، اور طحاوی وغیرہ کتب حدیث کی شکل میں بالکل محفوظ اور موجود ہے اور دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ باوثوق علمی اور گراں بہا سرمایہ ان معتبر کتابوں میں درج ہے۔
الغرض قرآن کریم کے بعد اس سے زیادہ مستند اور معتبر ذخیرہ دنیا کی تاریخ کے خزانہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تحریری سرمایہ ہی منکرینِ حدیث کے لیے قابلِ وثوق ہو سکتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زرین عہد سے تدوینِ کتبِ حدیث کے دور تک اس کی بھی کوئی کمی نہیں رہی جیسا کہ قارئین کرام ٹھوس حوالوں سے یہ پڑھ چکے ہیں۔ علاوہ بریں اسلام میں اصولِ تنقید اور درایت یعنی عقلی اور نقلی حیثیت سے روایت کو پرکھنے کے اصول و ضوابط الگ موجود ہیں اور ان اصول و قواعد کے ذریعے بخوبی احادیث کی تصحیح یا تضعیف کی جا سکتی ہے۔ اور روات کی چھان بین اور تحقیق میں اس درجہ دیانت داری اور حق گوئی سے کام لیا گیا ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی اور یہ کارروائی اہلِ اسلام کے مفاخر میں شامل ہے۔ مشہور عربی دان فاضل ڈاکٹر اس پرنگر جرمنی کا مقولہ آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہے: ’’نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے‘‘۔ (بلفظہٖ حاشیہ سیرۃ النبیؐ ج ۱ ص ۶۴ از مولانا شبلیؒ)۔
رشاد خلیفہ - ایک جھوٹا مدعئ رسالت
پروفیسر غلام رسول عدیم
ایک اطلاع کے مطابق امریکہ کے ایک مشہور مدعی رسالت ڈاکٹر رشاد خلیفہ کو ۳۱ جنوری ۱۹۹۰ء رات دو بجے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر انٹرنیشنل عربی اخبار ’’المسلمون‘‘ کے حوالے سے ہفت روزہ ختم نبوت کراچی بابت ۹ تا ۱۶ مارچ ۱۹۹۰ء (جلد ۸ شمارہ ۳۸) میں چھپی ہے۔ ڈاکٹر رشاد خلیفہ کا مسکن امریکہ کی ریاست Arizona (اریزونا) کا شہر Tucson (ٹوسان) تھا۔ وہ ایک عرصۂ دراز سے بظاہر قرآن و اسلام کی خدمت کر رہا تھا مگر بباطن اسلام کی جڑیں کاٹ رہا تھا تا آنکہ تین سال قبل رسالت کا دعوٰی کر دیا۔
تاریخ شاہد ہے ملحدین و دین بیزار افراد نے اصلاحِ دین کے پردے میں اپنے ناپاک عزائم کے لیے جو تحریکیں اٹھائیں انہیں پروان چڑھانے کے لیے ابتدائی مراحل میں وہ حمایتِ دین کے علم بردار بن کر ابھرے۔ اسی فریب کاری سے عوام میں مقبولیت حاصل کی اور پھر جب ان کی تجدیدی مساعی کی ساکھ قائم ہو گئی تو اپنی دوفطرتی کا اس انداز سے مظاہرہ کیا کہ ان کی مقصد برآری بھی ہونے لگی اور ناپختہ کار لوگوں کا ایک ہجوم بھی ان کے ساتھ گمراہی کی راہوں پر چل نکلا۔ ایسے دسیسہ کاروں کا طرزِعمل یہ رہا ہے کہ وہ اپنے باطل خیالات کی پرورش کے لیے کسی قدر اس میں سچائی بھی شامل کر لیتے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کوئی ان کی آواز پر کان نہ دھرتا۔ آغازِکار ہی سے ان کا پول کھل جاتا۔ ایسی تحریکوں کی مثالیں ماضی بعید میں بھی ملتی ہیں اور ماضی قریب میں بھی۔
آغازِ اسلام میں اہلِ تشیع نے بھی کچھ ایسا ہی انداز اختیار کیا۔ اکثر صحابہ کرامؓ کی تکفیر و تفسیق اور ازواجِ مطہرات کی تنقیص کے جراثیم سوسائٹی میں پھیلانے کے لیے اہلِ بیتؓ کی محبت کا سہارا لیا۔ صحابہ کرامؓ سے بے اعتنائی کے نتیجے کے طور پر ان احادیث نبویہؐ سے گلوخلاصی کرائی جو ان صحابہؓ سے مروی تھیں۔ ان صحابہؓ پر بداعتمادی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ان کی مرویات کو رد کر دیا جائے۔ یوں وہ اہلِ بیتؓ سے محبت کے دعوے کے باوجود صحابہؓ کی پاکیزہ سیرتوں اور عملاً سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند اقوال و فرمودات اور آپؐ کی سیرتِ طیبہ سے علمی و عملی استفادے سے محروم رہ گئے۔
انیسویں صدی کے وسط آخر اور پھر بیسویں صدی کے پہلے عشرے میں برصغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی دعوٰئ نبوت سے پہلے آریہ سماجیوں اور مسیحیوں کے خلاف مناظرِ اسلام بن کر اٹھا۔ اسلام کی صداقت کی حمایت میں مقالے لکھے، مناظرے کیئے، تقریریں کیں مگر جب اپنی مقصد برآری کے لیے دور تک آگے نکل گیا تو مجدد، محدث، مثیل مسیح حتٰی کہ دعوٰئ نبوت سے بھی گریز نہ کیا۔
کچھ ایسا ہی حال عالیجاہ محمد کا تھا۔ عالیجاہ نے سیاہ فام امریکیوں کو اسلام اور قرآن کی طرف بلایا۔ بظاہر یہ دعوت بڑی خوش آئند تھی مگر امتدادِ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک نسلی تحریک زیادہ بن گئی اور دینی کم، جس میں سیاہ فام افریقی دیوتا تھے اور سفید فام امریکی ان کے پیدا کردہ شیطان۔
بعینہٖ یہی حال گذشتہ چند برسوں سے ڈاکٹر رشاد خلیفہ کا تھا۔ رشاد خلیفہ نے ایک داعئ اسلام کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا مگر اس کی دعوت ایک خاص نقطہ پر مرکوز تھی، اسے اسلاف کی دینی خدمات اور قرونِ خیر کی خیریت پر اعتماد نہ تھا۔ اس کی تجدد پسندانہ اور ریاضیاتی ساخت و باخت نے دین کی آڑ میں ایک نئی گمراہی کو جنم دیا۔ ۱۹ کا عدد اس کی تمام تر صلاحیتوں کا مرکز تھا۔ ۱۹ کے عدد سے وہ بظاہر نظر اپنے دو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔
(۱) قرآن دنیا کی طرف خدا کا آخری پیغام ہے اور ۱۹ کا عدد اس کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا کا واحد ہونا حروف ابجد کے اعتبار سے ثابت ہے۔
و + ا + ح + د
۶ + ۱ + ۸ + ۴ = ۱۹
یہی وحدانیتِ الٰہی قرآن کا مقصودِ اصلی ہے۔
(۲) قرآن ہر طرح کی آمیزش، نقص و زیادت سے پاک ہے۔
اس نے اپنے پہلے دعوٰی کی تردید اس تعبیر سے کر دی جو سنت کے انکار پر مبنی تھی، اس نے کہا کہ سنت کی پیروی گمراہی اور بت پرستی ہے۔ یوں منکرِ حدیث ہو کر رشاد خلیفہ قرآنی بصیرت کھو بیٹا۔ اس کی کتاب The Computer Speaks: God's Message to the World نے دنیا کو چونکا دیا اور لوگ اس کی قرآن میں ریاضیاتی کوششوں کے معترف ہو گئے۔
جہاں تک اس کے دوسرے مقصد کا تعلق ہے وہ اس سے بھی انحراف کر گیا۔ جب بعض قرآنی آیات اس کے خودساختہ ریاضیاتی کلیوں کے مطابق نہ نکلیں تو اس نے ان آیات ہی سے انکار کر دیا۔ مثلاً اس نے سورۂ توبہ کی آخری دو آیتوں کو وضعی اور الحاقی کہہ کر خود ہی قرآن میں عدم نقص و زیادت کی تردید کر دی۔ اس نے کہا:
’’کمپیوٹر نے ایک تاریخی جرم کا اظہار کر دیا۔ خدا کے کلام میں تحریف۔ قرآن میں دو وضعی آیات نکل آئیں۔ قرآن کے ہندسی ضابطے میں نو (۹) نقائص دریافت کر لیے گئے۔ یہ تمام نو نقائص سورت نمبر ۹ کی آخری دو آیتوں میں پائے گئے ہیں۔‘‘
بہت سے نو مسلم رشاد خلیفہ کو سچا رسول سمجھنے لگے کیونکہ وہ بڑے وثوق سے دعوٰی کرتا کہ وہ اپنی اس تحقیق سے قرآن کی زبان و بیان کی پاکیزگی کو ثابت کر رہا ہے۔ اس کے جھانسے میں آنے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو علمِ دین کا ضروری علم نہیں رکھتے، اسلام تو قبول کر لیتے ہیں، ان کی علمی سطح مبادیات سے اوپر نہیں جاتی۔ تاہم بعض ثقہ قسم کے علماء نے اس کی گرفت کی اور اس کے ان خودساختہ نظریات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، باوجودیکہ وہ ان سے قرآن ہی کی حقانیت ثابت کرتا دکھائی دیتا تھا۔
آج سے دس برس پہلے ممتاز عالمِ دین مولانا عبد القدوس ہاشمی نے بجا طور پر کہا تھا کہ عددیات کا باطل علم قدیم اساطیری ادبوں کی پیداوار ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ عوام میں جو ۶۸۷ کے عدد کی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی نسبت سے اہمیت تسلیم کی جاتی ہے مولانا ہاشمی نے اس کو بے جواز اور بے کار بتایا۔ قرآنی آیات کو عددی شکلیں دے کر ان سے تعویذ بنانا بھی بیکار مشغلہ اور ضعیف الاعتقادی کا نتیجہ قرار دیا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ ۱۹ کے عدد کی اہمیت سب سے پہلے نویں صدی عیسوی میں قرامطہ کے ہاں ملتی ہے، پھر ان قرامطہ کی بگری ہوئی شکل بہائی فرقہ کے ہاں ۱۹ کا عدد بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہائی فرقۂ باطلہ کے بانی محمد علی باب کی تاریخ پیدائش ۱۸۱۹ء ہے۔ ان اعداد کا مجموعہ ۹+۱+۸+۱=۱۹ بنتا ہے۔ بہائیوں نے ۱۹ کے عدد کو مرکزِ کائنات مانا اور اسے اسرارِ کائنات کا اصل سرچشمہ قرار دے لیا ہے۔ بہائیوں نے سال کے ۱۹ مہینے قرار دیے اور ہر مہینے کے ۱۹ دن بنائے، یوں ان کا کیلنڈر بھی ۱۹ کے عدد کے گرد گھومنے لگا۔
یہی ۱۹ کا ہندسہ جو بہائیوں کے ہاں بڑا مقدس اور معنی خیز ہندسہ قرار دیا جاتا تھا اسی پر رشاد خلیفہ نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کی ٹھان لی۔ اسے مرکز بنا کر اس نے کئی کتابیں لکھیں جن میں اہم یہ ہیں:
The Perpetual Miracle of Muhammad 1976
Mujiza Al-Quran Al-Karim 1980
The Final Scripture 1981
Quran, Hadith and Islam 1982
Quran: Visual Presentation of the Miracle 1982
عام مسلمانوں کے علاوہ رشاد کے بھرّے میں آنے والوں میں مشہور مناظرِ اسلام احمد دیدات کا نام سرِفہرست ہے۔ وہ اس کی کنجکاری سے بہت متاثر ہوئے۔ ۱۹۷۹ء میں انہوں نے ایک مختصر کتاب Al-Quran an Ultimate Miracle لکھ کر رشاد کے افکار و دلائل کا خلاصہ پیش کیا۔ بعد ازاں اس موضوع پر احمد دیدات کا ایک لیکچر بعنوان Al-Quran a Visual Miracle بھی پوری دنیا میں ٹیپ کر کے مفت تقسیم کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد رشاد خلیفہ نے اس بات کا دعوٰی کیا کہ اس نے ۱۹ کے عدد کی مدد سے قیامت کی صحیح تاریخ بھی معلوم کر لی ہے۔ جب اس کی جسارت یہاں تک آ پہنچی تو احمد دیدات سمیت بہ سے مسلمان اس سے بدظن ہو گئے۔ اس کے معترفین نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی، کئی تاثراتی و جذباتی مضمون لکھے گئے۔ اس کی اس دیدہ دلیری کے پیشِ نظر جید علماء سے استفتاء کیا گیا۔ دنیائے اسلام کے معروف ترین عالمِ دین شیخ عبد اللہ بن عبد العزیز بن باز (سعودی عرب) نے اس کے ارتداد کا فتوٰی دیا۔
اس دوران میں رشاد خلیفہ نے مصری سکونت ترک کر کے امریکہ میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ امریکہ کی ریاست اریزونا کے شہر توسان میں بیٹھ کر ایک ماہانہ خبرنامہ جاری کیا جس کی بے شمار کاپیاں امریکہ اور کینیڈا کے سارے اسلامی حلقوں میں مفت تقسیم کیں۔ محدود علم کے نومسلم اس کی گرفت میں جلد آ جاتے بالخصوص وہ خواتین جو پردے کی حامی نہ تھیں اور اسلامی لباس کے حق میں نہ تھیں وہ اس کے جھانسے میں زیادہ آتیں کیونکہ رشاد خلیفہ نے ساتر لباس کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ عورتیں اور مرد ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔
رشاد خلیفہ کے عقائدِ باطلہ اور ان کی تردید ایک مستقل مقالے کا متقاضی ہے; تاہم اس مدعئ رسالت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ۱۹ حروف پر مشتمل بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی آیت قرآن کا ایک معجزاتی عددی ضابطہ ہے۔ یہ معجزاتی ضابطہ سورہ مدثر کی آیت ۳۰ کا منبٰی ہے اور یہ آیت ’’علیھا تسعۃ عشر‘‘ پورے قرآن کی عددی و ریاضیاتی معجزنمائی کی اساس ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ ۱۹ اور اس کی جمعی، تقسیمی اور ضربی شکلیں پورے قرآن کو محیط ہیں۔ جو آیاتِ قرآنی اس ضابطے پر پوری نہیں اترتیں وہ وضعی ہیں۔
حروفِ مقطعات جو قرآن مجید کی ۲۹ سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں ان میں اس نے عددی اسرار تلاش کیے ہیں اور دعوٰی کیا ہے کہ قرآن جیسی ادبی کتاب میں ریاضیاتی صحت ضابطہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ کام انسانی قوت سے ماوراء ہے۔ چونکہ آج کا دور انسان کے صلبی اولاد کے بجائے اس کی معنوی اولاد معجزاتی چپ (سیلیکون چپ جس کی مدد سے کمپیوٹر کا انقلاب آیا) اور الیکٹرانی ساحروں یعنی کمپیوٹروں کا دور ہے، قرآن اس چیلنج کو قبول کر کے کمپیوٹر کے لوازم پر پورا اترتا ہے، اس سے اس کا معجزہ اور وحی ہونا ظاہر ہے۔ مزید یہ کہ ۱۹ اور اس کی مختلف ہندسی ہیئتیں، وہ ضربی ہوں جمعی ہوں یا تقسیمی، قرآن کی صحیح تعبیر پیش کرتی ہیں۔
رشاد خلیفہ کا یہ بھی دعوٰی ہے کہ وہ رسول ہے نبی نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے خاتم الرسل نہیں کہا۔ رشاد خلیفہ نے اپنی کتاب Quran: Visual Presentation of Miracle کے پہلے ۲۴۷ صفحات میں نام نہاد ’’۵۲ طبعی حقائق‘‘ پیش کر کے اعداد و شمار کے گوشوارے دیے ہیں۔ عام قاری ان سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن جب ان پر گہرا غور کیا جائے تو اس مدعئ رسالت کے افکار کا تاروپود بکھر کر رہ جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ابو امینہ بلال فلپس کی کتاب The Qur'an's Numerical Miracle: Hoax and Heresy لائق مطالعہ ہے۔
تحریکِ پاکستان اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(الشبان المسلمون سیالکوٹ کے زیر اہتمام اسلامک پبلک سکول (باجوہ اسٹریٹ، رنگ پورہ، سیالکوٹ) میں تحریک پاکستان کے عظیم راہنما شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مدیر الشریعہ نے حسب ذیل خطاب کیا۔ ادارہ الشریعہ)
بعد الحمد والصلوٰۃ۔ آج کی یہ تقریب الشبان المسلمون کے زیراہتمام تحریک پاکستان کے عظیم راہنما شیخ الاسلام علامہ شبیر احمدؒ عثمانی کی خدمات اور جدوجہد کے تذکرہ کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے پروفیسر محمد عبد الجبار صاحب اور مولانا محمد انذر قاسمی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں جبکہ پروفیسر میاں منظور احمد صاحب جو حضرت علامہ عثمانی کے شاگرد بھی ہیں میرے بعد اظہارِ خیال فرمانے والے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ حضرت مولانا شبیر احمدؒ عثمانی کی جدوجہد اور خدمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں۔ تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔
حضراتِ محترم! شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمدؒ عثمانی کی عملی زندگی کو میں تین حصوں میں تقسیم کروں گا:
- ایک حصہ اس دور پر مشتمل ہے جب آپ نے دیوبند اور ڈابھیل میں علمی خدمات سرانجام دیں، ہزاروں تشنگانِ علوم کو قرآن و سنت کے معارف سے سیراب کیا، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ العزیز کے علمی جانشین کی حیثیت سے قرآن کریم کے حواشی مکمل کیے جو قرآن کریم کے اردو تراجم اور حواشی میں آج بھی سب سے زیادہ وقیع اور جامع شمار کیے جاتے ہیں، اور مسلم شریف کی شرح فتح الملہم لکھ کر علمی حلقوں سے خراجِ تحسین وصول کیا۔ جبکہ میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی علمی خصوصیت یہ ہے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی طرح علامہ عثمانی بھی اپنے دور کے سب سے بڑے متکلم تھے۔ انہوں نے اسلامی نظریات و عقائد اور احکام و قوانین کو جس قوتِ استدلال کے ساتھ پیش کیا اس کی مثال اس دور میں نہیں ملتی۔ اور علامہ عثمانی کی علمی عظمت کے اعتراف کی ایک جھلک اس واقعہ کے حوالہ سے دیکھی جا سکتی ہے جو میں نے حضرت مولانا عبید اللہ انورؒ کی زبانی سنا۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ نے ایک دور میں شیرانوالہ لاہور میں اکابر علماء دیوبند کے اجتماع کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا حسین علیؒ آف واں بھچراں اور حضرت دین پوریؒ جیسے عظیم اکابر بھی موجود تھے اور شیخ اسلام علامہ شبیر احمدؒ عثمانی بھی تشریف فرما تھے۔ اجتماع میں لاہور کے سرکردہ حضرات کو بھی مدعو کیا گیا تھا جن میں سرفہرست علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم تھے۔ اس اجتماع میں جب حضرت علامہ شبیر احمدؒ عثمانی نے خطاب شروع کیا تو علامہ اقبالؒ اسٹیج پر تشریف فرما تھے لیکن چند لمحوں کے بعد وہ اسٹیج سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے سامعین میں بیٹھ گئے کہ اس پیکرِ علم کا خطاب سامنے بیٹھ کر طالب علموں کی طرح سننا چاہیے۔ یہ علامہ عثمانی کی علمی عظمت کا اعتراف ہے اور اس سے ان کے علمی مقام و مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ شبیر احمدؒ عثمانی کی علمی خدمات اور جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ پہلو میں ان کے شاگرد جناب پروفیسر میاں منظور احمد صاحب کے لیے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اس دور کی طرف جس میں علامہ عثمانی نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے یہ کردار تنہا نہیں ادا کیا بلکہ علماء کی ایک جماعت کے ساتھ تحریک پاکستان میں شرکت کی اور قیام پاکستان کی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔
- ہمارے ہاں ایک بات تسلسل کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ علمائے دیوبند نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی اور وہ قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ یہ تاثر ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت عام کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد کارفرما ہے۔ اس سلسلہ میں مقالات و مضامین کی اشاعت ہو رہی ہے اور اخبارات میں مہم کے انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال ایک صاحب نے اس تاثر کو بنیاد بنا کر ایک اور مقدمہ کھڑا کیا ہے جو اس مہم کا اصل مقصود ہے۔ انہوں نے اپنے مسلسل مضمون میں یہ مقدمہ قائم کیا کہ علماء نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی اور قوم نے پاکستان بنا کر علماء کے موقف کو مسترد کر دیا جبکہ تحریک پاکستان کی قیادت جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے کی، اس لیے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے علماء کی بیان کردہ تعبیر و تشریح کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا بلکہ وہ تعبیر و تشریح اختیار کی جائے گی جو ان کے بقول تعلیم یافتہ طبقہ قرآن و سنت کے لیے ازسرنو طے کرے گا۔
یہ ایک نئی گمراہی کا دروازہ ہے جسے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس مقصد کے لیے یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے کہ علماء نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی تاکہ اس مفروضے کو نئی گمراہی کی فکری اساس بنایا جا سکے۔ حالانکہ یہ خلاف واقعہ بات ہے اور جھوٹ ہے کیونکہ سب علماء نے تحریک پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ یہ درست ہے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ تحریک پاکستان کی مخالفت کرنے والے علماء نے قیام پاکستان کی صورت میں جن خدشات و خطرات کا اظہار کیا تھا، پاکستان بننے کے بعد کے چالیس سالہ دور نے ان کی تصدیق کی یا ان کو رد کیا ہے۔ میں اس بحث کی طرف بھی نہیں جاؤں گا کہ قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والے علماء کا سیاسی تشخص تقسیم ہند کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے لیے کس حد تک سہارا بنا ہے اور ان علماء کے سیاسی تشخص نے ان مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا رول ادا کیا ہے۔ ان مباحث میں الجھے بغیر میں کھلے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ علمائے دیوبند کے ایک بڑے طبقہ نے قیام پاکستان کے خلاف کام کیا تھا۔ لیکن اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علمائے دیوبند ہی کے ایک بڑے طبقے نے قیام پاکستان کی جدوجہد کا ساتھ دیا تھا اور ان کے سرخیل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمدؒ عثمانی تھے۔ تحریک پاکستان کا ساتھ دینے والے انہی علماء میں حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانویؒ بھی تھے جن کے بارے میں خود قائد اعظم مرحوم کا یہ مقولہ تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ ’’ہمارے ساتھ ایک اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کا علم ہندوستان کے تمام علماء کے علم پر بھاری ہے۔‘‘ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی ہدایت پر اور حضرت علامہ شبیر احمدؒ عثمانی کی قیادت میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تحریک پاکستان میں عملاً شریک ہوئی اور فردًا فردًا نہیں بلکہ ایک باقاعدہ جماعت کی صورت میں انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔
آج یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا، میں اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ تنہا مسلم لیگ نے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جماعت بھی تھی جو تحریک پاکستان میں شریک تھی اور اس جماعت کا نام جمعیۃ علماء اسلام ہے۔ جمعیۃ علماء اسلام کا قیام ۱۹۴۵ء میں کلکتہ میں عمل میں لایا گیا اور علامہ شبیر احمدؒ عثمانی کو اس کا سربراہ چنا گیا ۔ اس جماعت نے باقاعدہ پلیٹ فارم قائم کر کے مسلم لیگ کے ساتھ تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ اس میں مولانا اطہر علیؒ جیسے بزرگ تھے، علامہ ظفر احمدؒ عثمانی، مولانا غلام مرشدؓ، مولانا راغب احسنؒ، مولانا مفتی محمد شفیعؒ اور دیگر علماء تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کا نظریاتی تشخص اجاگر کیا۔ اور مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ تحریک پاکستان کا نظریاتی اور اسلامی تشخص انہی علماء کی وجہ سے اجاگر ہوا۔ ان کے علاوہ دوسرے علماء بھی تھے۔ مولانا عبد الحامدؒ بدایونی بھی تھے، پیر صاحبؒ آف مانکی شریف بھی تھے اور مولانا محمد ابراہیمؒ سیالکوٹی بھی تھے۔ میں تحریک پاکستان میں ان میں سے ہر کردار کا اعتراف کرتا ہوں اور اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک پاکستان کو اگر اسلامی تحریک سمجھا گیا ہے اور اس کے نظریاتی تشخص پر لوگوں کا اعتماد قائم ہوا ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہوا ہے اور عوام نے ان علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے ذہنوں اور دلوں میں تحریک پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی تحریک کی حیثیت سے جگہ دی ہے۔ ورنہ اگر مسلم لیگی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک پاکستان کا نظریاتی تشخص اس کی وجہ سے قائم ہوا تھا تو یہ بات خود فریبی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قیام پاکستان کے وقت دو علاقوں کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا کہ ان علاقوں کے عوام سے ریفرنڈم کے ذریعے رائے لی جائے گی کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک صوبہ سرحد تھا جہاں کانگریس کی حکومت تھی اور ڈاکٹر خان مرحوم اس کے وزیر اعلیٰ تھے اور دوسرا سلہٹ کا علاقہ تھا۔ ان علاقوں میں ریفرنڈم جیتنا کوئی آسان بات نہ تھی اور ریفرنڈم کے لیے جب مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا تو علامہ شبیر احمدؒ عثمانی اور ان کے رفیق کار علامہ ظفر احمدؒ عثمانی سے درخواست کی گئی کہ وہ اس مہم کی قیادت کریں۔ چنانچہ علامہ عثمانی نے صوبہ سرحد میں پیر صاحب آف مانکی شریف کے ہمراہ اور مولانا ظفر احمدؒ عثمانی نے سلہٹ میں انتخابی مہم کی قیادت کی۔ ان علاقوں میں مسلم لیگ کی پوزیشن کمزور تھی لیکن یہ ان علماء کی مہم تھی کہ ریفرنڈم کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت کراچی میں علامہ شبیر احمدؒ عثمانی اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمدؒ عثمانی کے ہاتھوں قومی پرچم لہرانے کا تاریخی واقعہ دراصل ان دو بزرگوں کے اس کردار اور جدوجہد کا عملی اعتراف تھا جو انہوں نے قیام پاکستان میں کی۔
- حضراتِ محترم! شیخ الاسلام علامہ شبیر احمدؒ عثمانی کی جدوجہد کا تیسرا دور قیام پاکستان کے بعد دستور ساز اسمبلی میں ان کی جدوجہد کا دور ہے جب انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے پاکستان کی نظریاتی بنیاد کے تعین کی جنگ لڑی۔ اس حوالہ سے یہ بحث الگ گفتگو کی متقاضی ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نعرہ پر بنا اور جسے دنیا کی پہلی اسلامی نظریاتی مملکت کا عنوان دیا گیا، اس ملک کے قائم ہوتے ہی اس کی دستور ساز اسمبلی میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگیا کہ ملک کا دستور اسلامی ہونا چاہیے یا سیکولر بنیادوں پر ملک کا نظام ترتیب دیا جائے۔ یہ سوال آخر کیسے اٹھا اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس پر مستقل بحث کی ضرورت ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے ریکارڈ کا تجزیہ کیا جائے، اسے کھنگالا جائے اور اس ہاتھ کو تلاش کیا جائے جس نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو سیکولرازم کی بحث میں الجھا دیا۔
بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دستور ساز اسمبلی میں نظریاتی اسلامی دستور کی مخالفت کی گئی اور مُلااِزم، پاپائیت اور تھیاکریسی کے طعنے کسے گئے ۔ اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ دستور ساز اسمبلی کا عمومی رجحان بظاہر غیر مذہبی نظام کی طرف ہو چکا تھا لیکن شیخ الاسلام علامہ شبیر احمدؒ عثمانی نے اس مہم کا سامنا کیا اور تمام اعتراضات کا منطق و استدلال کے ساتھ جواب دیتے ہوئے بالآخر اسمبلی کو قائل کر لیا اور قرارداد مقاصد منظور کرا کے پاکستان کی نظریاتی اسلامی بنیاد ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ قرارداد مقاصد کی بنیاد اس بات پر ہے کہ حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور پاکستان کے عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین نافذ کریں گے۔ قرارداد مقاصد کو نظرانداز کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں رہی اور اس قرارداد کے ذریعے علامہ شبیر احمدؒ عثمانی نے پاکستان کی اسلامی بنیاد کا ہمیشہ کے لیے تحفظ کر دیا۔
اس موقع پر ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ غلطی اگرچہ خلوص سے ہو مگر اس کے نتائج بہرحال سامنے آتے ہیں۔ مجھے ۱۹۸۷ء میں ایران جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کے لیڈروں سے ایرانی انقلاب کے مراحل کے بارے میں گفتگو کا موقع ملا۔ ایک ایرانی لیڈر نے اس موقع پر مجھ سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایرانی علماء نے پندرہ بیس سال کی محنت کے ساتھ انقلاب بپا کر دیا لیکن پاکستان کے علماء کرام جن کی جدوجہد دو سو سال تک آزادی کے لیے تھی اور آزادی کے بعد چالیس سال سے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی جدوجہد کے ثمرات سامنے نہیں آرہے اور انہیں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے اس سوال کے جواب میں اپنے ذہن کے مطابق ان اسباب و عوامل کا ذکر کیا جو پاکستان میں نفاذ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اس پر ایرانی لیڈر نے کہا کہ جناب بات یہ نہیں بلکہ اصل قصہ یہ ہے کہ ایرانی علماء نے بادشاہت کے خلاف تنہا جنگ نہیں لڑی، اس جنگ میں ایران کے نیشنلسٹ اور کمیونسٹ حلقے بھی ان کے ساتھ تھے۔ مذہبی قیادت، کمیونسٹ تودہ پارٹی اور ڈاکٹر مصدق کی نیشنلسٹ پارٹی نے مل کر بادشاہت کو شکست دی لیکن شاہِ ایران کے ملک سے باہر چلے جانے کے بعد ایرانی علماء نے اقتدار دوسروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ بتدریج انہیں منظر سے ہٹا کر اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے وہ انقلاب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے اور اس پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ جبکہ پاکستان کے قیام کے بعد وہ علماء جنہوں نے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ خلوص کا شکار ہوگئے اور مدارس و مساجد پر قناعت کرتے ہوئے انہوں نے اقتدار کا راستہ دوسرے لوگوں کے لیے صاف کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ملک کا نظام بھی انہی کی مرضی کے مطابق ہی چلنا ہے۔
یہ ایک ایرانی لیڈر کی بات کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ ممکن ہے یہ سو فیصد درست نہ ہو لیکن سو فیصد غلط بھی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے اگر آپ اس جسارت پر معاف فرمائیں تو عرض کروں گا کہ برصغیر کی تاریخ میں دو بڑی غلطیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دونوں غلطیاں خلوص کے ساتھ ہوئیں۔ ایک غلطی احمد شاہ ابدالیؒ کی ہے جس نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دے کر اقتدار انہیں مغل شہزادوں کے حوالے کر کے وطن واپس لوٹ گیا۔ وہ اس حقیقت کا ادراک نہ کر سکا کہ مغل شہزادوں میں اب ہندوستان کا اقتدار سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مغل شہزادے اقتدار نہ سنبھال سکے اور بالآخر برطانوی استعمار کو یہاں پاؤں جمانے کا موقع مل گیا۔ دوسری بڑی غلطی پاکستان بننے کے فورًا بعد علماء سے ہوئی کہ انہوں نے اقتدار میں شرکت اور حصہ داری پر اپنا دعویٰ نہیں جتایا حالانکہ یہ ان کا حق تھا، لیکن انہوں نے خلوص کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اقتدار میں شریک نہیں ہونا بلکہ باہر رہ کر اقتدار والوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں اور خدا جانے کب تک ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
الغرض علامہ شبیر احمدؒ عثمانی کی جدوجہد کا یہ دور بھی بڑا تابناک ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر کے قرارداد مقاصد منظور کرائی اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو سیکولرازم کی بنیاد پر دستور طے کرنے سے روک دیا۔
حضراتِ گرامی قدر! شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمدؒ عثمانی کی یہ جدوجہد ہمارے ذمہ قرض ہے اور یہ قرض ہم نے بہرصورت ادا کرنا ہے۔ قرارداد مقاصد منظور کرا کے ملک کی اسلامی نظریاتی بنیاد کا تعین علامہ عثمانی نے کیا تھا اور ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنانا اور مکمل اسلامی نظام کا نفاذ و غلبہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برآ ہونے کی توفیق ارزانی فرمائیں، آمین یا الہ العالمین۔
آیت ’’توفی‘‘ کی تفسیر
مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ
سورۃ آل عمران کی آیت ۵۵ یوں ہے:
اِذْ قَالَ اللہُ یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّ وَمُطَہِّرُکَ الخ۔
ترجمہ از شاہ عبد القادر صاحبؒ: ’’جس وقت کہا اللہ نے اے عیسٰیؑ! میں تجھ کو پھر لوں گا (یعنی تجھ کو لے لوں گا اور قبض کر لوں گا زمین سے) اور اٹھا لوں گا اپنی طرف (یعنی اپنے آسمان کی طرف جو کرامت کی جگہ اور ملائکہ کا مقام ہے) اور پاک کر دوں گا کافروں (کی ہمسائیگی اور برے قصد) سے‘‘۔
پہلا معنٰی
اس صورت میں لفظ ’’مُتَوَفِّیْکَ‘‘ کا معنی ’’قَابِضْکَ‘‘ کا ہے جیسے کہتے ہیں ’’تَوَفَّیْتُ مَالِی‘‘ یعنی قبض کیا اور واپس لیا میں نے اپنے مال کو اور یہی معنی جلالین میں مذکور ہیں۔
دوسرا معنی
یا لفظ ’’متوفیک‘‘ کا معنی ’’مُسْتَوفِی اَجَلِکَ‘‘ کے ہیں اور معنی یوں ہیں: ’’اے عیسٰی! تجھ کو تیری زندگی کی مدت پوری دوں گا‘‘ (یعنی تو اپنی عمر مقرر تک پہنچے گا اور مخالف تجھے قتل نہ کر سکیں گے)۔
تیسرا معنی
یا بمعنی ’’مُسْتَوفِی عَمَلِکَ‘‘ کے ہے اور اس میں بشارت ہے عیسٰیؑ کو ان کی اطاعت اور اعمال کی قبولیت کا اور معنی یوں ہے: ’’اے عیسٰی! میں پورے اور کامل کروں گا تیرے اعمال کو‘‘۔
چوتھا معنی
یا متوفی بمعنی ’’مستوفی‘‘ کے ہے اور مضاف محذوف نہیں ہے اور معنی یوں ہے: ’’اے عیسٰی! میں پورا اور کامل لے لوں گا تجھ کو (یعنی روح اور بدن سمیت)‘‘۔ اور اس صورت میں ارشاد سے فائدہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف عیسٰیؑ کی روح مع بدن کے اٹھائی گئی ہے، کوئی فقط روح کو بغیر بدن کے نہ سمجھے۔
پانچواں معنی
یا متوفی بمعنی ’’اَجْعَلُکَ کَالْمُتَوَفِّی‘‘ کے ہے اور معنی یوں ہے: ’’اے عیسٰیؑ میں تجھ کو مردہ کی مانند کر دوں گا (یعنی زمین سے اثر و خبر کے انقطاع کے اعتبار سے)‘‘۔
چھٹا معنی
یا متوفیک بمعنی ’’مُتَوَفِیْ نَفْسَکَ بِالنَّوم‘‘ کے ہے جیسے سورہ زمر کی آیت ۴۲ یوں ہے:
اَللہُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِھَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِھَا الخ
’’یعنی اللہ کھینچ لیتا ہے جانوں کو جب وقت آتا ہے ان کے مرنے کا (اور کھینچ لیتا ہے) ان جانوں کو نیند میں جو نہیں مریں ۔۔۔‘‘
اس آیت میں لفظ متوفی کا اطلاق نیند کی حالت پر آیا ہے، پس اس صورت میں معنی یوں ہے: ’’اے عیسٰی! میں تجھ کو کھینچ لوں گا سوتے ہوئے (تاکہ آسمان کی طرف عروج کے وقت خوف نہ لگے)‘‘۔ اور ربیع بن انسؓ سے بھی روایت ہے کہ عیسٰیؑ نیند کی حالت میں اٹھائے گئے اور اسی طرح اس کے اور معانی ہیں۔ اور کسی معتبر مترجم یا مفسر نے نہیں لکھا کہ مسیح مر گیا پھر اٹھایا گیا۔ البتہ بیضاویؒ نے آخر میں ایک مجہول شخص کا قول قِیْلَ کے لفظ کے ساتھ نقل کیا ہے جو نصارٰی کے مذہب کے موافق ہے اور ایسے مجہول شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
(بتفسیر یسیر از ’’ازالۃ الشکوک ج ۱ ص ۱۵۳)
(انتخاب: حافظ محمد عمار خان ناصر)
’’کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن‘‘
ایک مشہور حدیث کا تحقیقی جائزہ
غازی عزیر
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شائع ہونے والا اردو ماہنامہ ’’تہذیب الاخلاق‘‘ مجریہ ماہ مئی ۱۹۸۸ء راقم کے پیشِ نظر ہے۔ شمارہ ہٰذا میں جناب مولوی شبیر احمد خاں غوری (سابق رجسٹرار امتحانات عربی و فارسی بورڈ سرشتہ تعلیم الٰہ آباد، یو۔پی) کا ایک اہم مضمون زیرعنوان ’’اسلام اور سائنس‘‘ شائع ہوا ہے۔ آں موصوف کی شخصیت برصغیر کے اہلِ علم طبقہ میں خاصی معروف ہے۔ آپ کے تحقیقی مقالات اکثر برصغیر کے مشہور علمی رسائل و جرائد کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ آں محترم نے پیشِ نظر مضمون کے ایک مقام پر بعض انتہائی ’’ضعیف‘‘ اور ساقط الاعتبار احادیث سے استدلال کیا ہے جو ایک محقق کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ رقم طراز ہیں:
’’اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروؤں کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکوکاری اختیار کرنے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ خود کو اوصافِ حمیدہ سے متصف کریں اور ان اوصافِ حمیدہ کے چندن ہار میں واسطۃ العقد علم و حکمت ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ وہ علم حاصل کریں ہر چند کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے انہیں انتہائی مشقت حتٰی کہ اقصائے عالم کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔
اطلبوا العلم ولو کان بالصین۔
(علم کو تلاش کرو خواہ وہ چین (اقصائے عالم) ہی میں کیوں نہ دستیاب ہو۔)
پھر اس ’’حکم ناطق‘‘ کو مزید مؤکد بنانے کے لیے اسے ’’فریضۃ‘‘ کے لفظ سے تعبیر کیا جس میں کوتاہی یا تہاون کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
طلب العلم فریضۃ علٰی کل مسلم و مسلمۃ۔
(علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔)
یہی نہیں بلکہ آپؐ نے فرمایا حکمت مومن کی متاعِ گم گشتہ ہے جہاں ملے وہ دوسروں کے مقابلے میں اسے لے لینے کا زیادہ حق دار ہے۔
کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن اینما وجد ھا فھوا حق بھا۔
شمعٔ رسالت کے پروانوں کو اس حکم کی تعمیل میں کیا پس و پیش ہو سکتا تھا، لہٰذا زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ امت مسلمہ علم و حکمت کے خزانوں کی امین ہو گئی۔‘‘ (ماہنامہ تہذیب الاخلاق، علی گڑھ ج ۷ شمارہ ۵ بمطابق ماہ مئی ۸۸ء ص ۲۹)
افسوس کہ آں محترم کی بیان کردہ یہ تینوں انتہائی ’’ضعیف‘‘ اور قطعًا ناقابلِ اعتبار ہیں۔ پہلی دونوں احادیث پر راقم کا ایک طویل تحقیقی مضمون سہ ماہی مجلہ جامعہ ابراہیمیہ سیالکوٹ عدد شمارہ ۱۱۔۱۲ بمطابق ماہ ذوالحجہ ۱۴۰۶ھ تا محرم ۱۴۰۷ھ ص ۲۶۔۳۸) میں تقریباً ڈھائی سال قبل شائع ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ مجلس التحقیق الاسلامی لاہور (پاکستان) اپنے مؤقر علمی ماہنامہ محدث لاہور (ج ۱۸ شمارہ ۱۰ بمطابق ماہ جون ۱۹۸۸ء ص ۴۱۔۶۰) میں اسی مضمون کو بالاقساط شائع کر رہی ہے۔ شائقین کے لیے یہ مضمون بھی لائقِ مراجعت ہے۔ زیر نظر مضمون میں محترم جناب غوری صاحب کی بیان کردہ تیسری حدیث ’’کلمۃ الحکمۃ الخ‘‘ اور اس کے جملہ طرق پر علمی بحث پیش کی جاتی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ عند المحدثین اس روایت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔
اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے اپنی ’’جامع‘‘ (جامع الترمذیؒ معہ تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۳۸۲۔۳۸۳ طبع دہلی و ملتان) کے ’’ابواب العلم‘‘ میں، ابن ماجہؒ نے اپنی ’’سنن‘‘ (ص ۳۱۷ حدیث نمبر ۴۱۶۹) کی ’’کتاب الزہد‘‘ میں، بیہقیؒ نے ’’مدخل‘‘میں اور عسکریؒ نے بطریق ابراہیم بن الفضل عن سعید المقبری عن ابی ہریرہؓ مرفوعاً روایت کیا ہے۔ خطیب تبریزیؒ نے اس حدیث کو ’’مشکوٰۃ المصابیح‘‘ مع تنقیح الرواۃ ج ۱ ص ۴۹ طبع لاہور میں، علامہ سخاویؒ نے ’’مقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتھرہ ص ۱۹۱۔۱۹۲ میں، امام ابن الجوزیؒ نے ’’علل امتناہیۃ فی الاحادیث الواہیہ ج ۱ ص ۸۸ میں، ملا علی قاری حنفیؒ نے ’’اسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ‘‘ ص ۱۸۶ میں، علامہ محمد اسماعیل عجلونی الجراحیؒ نے ’’کشف الخفاء و مزیل الالباس عما اشتھر من الاحادیث علی السنۃ الناس ج ۱ ص ۴۳۵ میں، علامہ محمد درویش حوت البیروتیؒ نے ’’اسنی المطالب فی احادیث مختلفہ المراتب ص ۱۳۳ میں، علامہ شیبانی اثریؒ نے ’’تمیز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث‘‘ ص ۱۳۸ میں، امام ابن حبانؒ نے ’’کتاب المجروحین‘‘ ج ۱ ص ۱۰۵ میں، امام عقیلی نے ’’ضعفاء الکبیر‘‘ ج ۱ ص ۶۱، علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ’’الدرر المنتثرة‘‘ ص ۱۹۴، اور ’’جامع الصغیر‘‘ میں، علامہ قضاعیؒ نے ’’مسند شہاب‘‘ میں، عسکری اور علامہ شیخ محمد ناصر الدین الابانی حفظہ اللہ نے ’’ضعیف الجامع الصغیر و زیادتہ‘‘ وغیرہ میں معمولی حک و اضافہ۔ خطیب ترمذیؒ نے ’’مشکوٰۃ‘‘ میں ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ والی حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں ’’المؤمن‘‘ کی بجائے ’’الحکیم‘‘ لکھا ہے حالانکہ ترمذیؒ میں ’’المؤمن‘‘ کے الفاظ ہی مروی ہیں۔ (مشکوٰۃ مع تنقیح الرواۃ ج ۱ ص ۴۹)۔ علامہ سخاویؒ نے ترمذیؒ کی روایت کے الفاظ اس طرح نقل کیے ہیں: ’’الکلمۃ الحکیمۃ الخ‘‘ (مقاصد الحسنہ ص ۱۹۲) حالانکہ اصل عبارت میں لفظ ’’الحکیمۃ‘‘ کے بجائے ’’الحکمۃ‘‘ موجود ہے (جامع ترمذیؒ مع تحفہ ج ۳ ص ۳۸) کے ساتھ وارد کیا ہے۔
اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام ترمذیؒ فرماتے ہیں:
ھذا حدیث غریب، لالغرفہ الوجہ وابراھیم بن الفضل المخزومی ضعیف فی الحدیث‘‘ (جامع ترمذیؒ مع تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۳۸۲۔۳۸۳)۔
امام ابن الجوزیؒ بھی فرماتے ہیں کہ ’’یہ حدیث صحیح نہیں ہے‘‘ (علل المتناہیہ لابن الجوزیؒ ج ۱ ص ۸۸) اس روایت کی سند میں ایک مجروح روای ’’ابراہیم بن الفضل المخزومی المدنی‘‘ موجود ہے جس کے متعلق ابن معینؒ فرماتے ہیں کہ ’’ضعیف ہے، اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی‘‘۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ’’کچھ بھی نہیں ہے‘‘۔ امام نسائیؒ فرماتے ہیں ’’متروک الحدیث ہے‘‘۔ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں ’’متروک ہے‘‘۔ علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں ’’فاحش الخطاء ہے‘‘۔ امام عقیلیؒ فرماتے ہیں ’’امام بخاریؒ کا قول ہے کہ منکر الحدیث ہے‘‘۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ ’’حدیث میں قوی نہیں ہے، ضعیف الحدیث ہے‘‘۔ امام ابن الجوزیؒ نے یحیٰیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ’’اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہوتی‘‘۔ ڈاکٹر عبد المعطی امین قلعجی فرماتے ہیں کہ ’’اس کے متروک ہونے پر ائمہ جرح والتعدیل کا اجماع ہے۔ حدیث کے تمام نقاد نے اس کی تضعیف کی ہے۔ مجھے ایسا کوئی فرد نظر نہیں آتا کہ جس نے اس کی توثیق کی ہو‘‘۔
’’ابراہیم بن الفضل المخزومی‘‘ کے تفصیلی ترجمہ کے لیے تاریخ یحیٰی بن معینؒ، علل لابن حنبلؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ، تاریخ الصغیر للبخاریؒ، معرفۃ والتاریخ للبسویؒ، ضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، جرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، مجروحین لابن حبانؒ، کامل فی الضعفاء لابن عدیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ، تقریب التہذیب لابن حجرؒ، ضعفاء والمتروکان للنسائیؒ، ضعفاء والمتروکون للدارقطنیؒ اور مجموع فی الضعفاء والمتروکین للسیروان وغیرہ ملاحظہ ہوں۔
اب ذیل میں اس باب میں وارد ہونے والی چند اور روایات اور ان کے طرق کا عملی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
اس حدیث کو قضاعیؒ نے ’’مسند شہاب‘‘ میں بطریق لیث بن ہشام بن سعد عن زید بن اسلم مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس میں یہ اضافی الفاظ موجود ہیں ’’حیث ما وجد المومن ضالۃ فلیجمعھا الیہ‘‘۔ عسکریؒ کی ایک دوسری حدیث بطریق عنبسہ بن عبد الرحمٰن عن شبیب بن بشیر عن انس مرفوعاً بھی مروی ہے جو اس طرح ہے ’’العلم ضالۃ المؤمن حیث وجدہ اخدہ‘‘۔ قضاعیؒ اور عسکریؒ کی ایک اور روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے ’’کلمۃ الحکمۃ ضالۃ کل حکیم فاذا وجد ھا فھو احق بھا‘‘۔ ابن عساکرؒ، ابن لالؒ، اور دیلمیؒ وغیرہ نے بطریق عبد الوہاب عن مجاہد عن علی مرفوعاً اس طرح بھی روایت کی ہے ’’ضالۃ المومن العلم کلما قیہ حدیثاً طلب الیہ اٰخر‘‘۔ دیلمیؒ نے اپنی مسند ج ۱ ص ۲۰ میں اور عفیف الدین ابوالمعالیؒ نے ’’فضل العلم‘‘ ج ۱ ص ۱۱۴ میں ابراہیم بن ہانی عن عمرو بن حکام عن ابوبکر عن زیاد بن ابی حسان عن انسؓ کے مرفوع طریق سے ایک اور حدیث اس طرح روایت کی ہے ’’احسبوا علی المومنین ضالتھم قالوا وما ضالۃ المومنین قال العلم‘‘۔ اسباب میں دیلمی کی ایک اور حدیث جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے اس طرح ہے ’’نعم الفائدۃ الکلمۃ من الحکمۃ یسمعھا الرجل فیھد بھا لاخیہ‘‘۔ دیلمیؒ نے اس باب میں ابن عمرؓ سے بھی ایک حدیث روایت کی جو اس طرح ہے ’’خد الحکمۃ ولا یضرک من ای وِعاء خرجت‘‘۔
ان تمام روایات میں سے قضاعیؒ کی زید بن اسلم والی مرفوع حدیث کے متعلق علامہ سخاویؒ اور علامہ عجلونیؒ فرماتے ہیں کہ ’’یہ روایت مرسل ہے‘‘ (مقاصد الحسنہ للسخاویؒ ص ۹۲ و کشف الخفا للعجلونیؒ ج ۱ ص ۴۳۵) لیکن اس میں صرف راوی ’’زید بن اسلم‘‘ ہیں جو کثرت سے ارسال کرتے ہیں (کذا فی التہذیب التہذیب لابن حجرؒ ج ۱ ص ۲۷۲) کی موجودگی ہی اکیلی علت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دو اور مجروح راوی بھی اس کی سند میں موجود ہیں یعنی لیث بن ابی سلیم الکوفی اور ہشام بن سعد۔
’’لیث بن ابی سلیم الکوفی‘‘ جن سے صحاح اور سنن وغیرہ میں مرویات موجود ہیں کی نسبت امام نسائیؒ فرماتے ہیں کہ ’’ضعیف ہے‘‘۔ امام ابن حجر عسقلانیؒ کا قول ہے کہ ’’صدوق تھے مگر آخر عمر میں اختلاط کرنے لگے تھے اور اپنی احادیث میں تمیز کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے‘‘۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں ’’مضطرب الحدیث تھے لیکن لوگ ان سے روایت کرتے ہیں‘‘۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں ’’یحیٰیؒ اور نسائیؒ نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن ابن معینؒ کا ایک اور قول ہے کہ ’’اس میں کوئی حرج نہیں‘‘۔ ابن صبانؒ بیان کرتے ہیں کہ ’’آخر عمر میں اختلاط کرتے تھے‘‘۔ امام عقیلیؒ کہ ’’ابن عیینہ لیث بن ابی سلیم کی تضعیف کیا کرتے تھے ۔۔۔ یحیٰی بن سعید لیث سے کوئی روایت بیان نہیں کرتے تھے‘‘۔
’’لیث بن ابی سلیم‘‘ کے تفصیلی ترجمہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ضعفاء والمتروکون للنسائیؒ، تاریخ یحیٰی بن معینؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ، ضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، جرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، مجروحین لابن حبانؒ، کامل فی الضعفاء لابن عدیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ، تقریب التہذیب لابن حجر اور مجموع فی الضعفاء والمتروکین للسیروان وغیرہ۔ (ضعفاء والمتروکون للنسائیؒ ترجمہ نمبر ۵۱۱، تاریخ یحیٰی بن معینؒ ج ۲ ص ۵۰۱۔۵۰۲)
اس طریق کا دوسرا مجروح راوی ’’ہشام بن سعد ابو عباد المدنی‘‘ ہے جس کی نسبت امام نسائیؒ فرماتے ہیں ’’ضعیف تھے‘‘۔ امام نسائیؒ کا ایک اور قول ہے کہ ’’قوی نہ تھے‘‘۔ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں ’’صدوق ہے لیکن اس کو وہم رہتا ہے‘‘۔ اس پر تشیع کا الزام بھی ہے۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں ’’امام احمدؒ کا قول ہے کہ حافظِ حدیث نہ تھے، یحیٰی القطانؒ ان سے کوئی روایت بیان نہیں کرتے تھے‘‘۔ امام احمدؒ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ’’محکم الحدیث نہ تھے‘‘۔ ابن معینؒ فرماتے ہیں کہ ’’نہ قوی تھے اور نہ ہی متروک‘‘۔ ابن عدیؒ کا قول ہے کہ ’’ضعف کے باوجود ان کی حدیث لکھی جاتی ہے‘‘۔
ہشام بن سعدؒ کے تفصیلی ترجمہ کے ضعفاء والمتروکون للنسائیؒ، ضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ، جرح والتعدیل لابن حاتمؒ، مجروحین لابن حبانؒ، کامل فی الضعفاء لابن عدیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، تقریب التہذیب لابن حجرؒ اور مجموع فی الضعفاء والمتروکین للسیروان وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔
عسکریؒ کے ثانی الذکر طریق میں ایک مجروح راوی ’’عنبہ بن عبد الرحمٰن‘‘ ہے جسے امام نسائیؒ اور امام ابن حجر عسقلانیؒ نے ’’متروک الحدیث‘‘ بتایا ہے۔ ابو حاتم الرازیؒ نے اس کو ’’وضع حدیث‘‘ کے لیے متہم کیا ہے۔ امام بخاریؒ نے اسے ’’ترک‘‘ کیا ہے۔ علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں ’’امام ترمذیؒ امام بخاریؒ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ذاہب الحدیث تھا‘‘۔ امام عقیلیؒ فرماتے ہیں ’’یحیٰیؒ کا قول ہے کہ وہ ضعیف تھا‘‘۔
’’عنبہ بن عبد الرحمٰن‘‘ کے تفصیلی ترجمہ کے لیے تاریخ یحیٰی بن معینؒ، تاریخ الکبیر بخاریؒ، تاریخ الصغیر بخاریؒ، ضعفاء الصغیر للبخاریؒ، ضعفاء والمتروکون للنسائیؒ، ضعفاء المتروکون للدارقطنیؒ، معرفۃ والتاریخ للبسویؒ، ضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، مجروحین لابن حبانؒ، جرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، کامل فی الضعفاء لابن عدیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، مجموع فی الضعفاء والمتروکین للسیروان، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ اور تقریب التہذیب لابن حجرؒ وغیرہ مطالعہ فرمائیں۔
اب دیلمیؒ کی احادیث پر ناقدانہ بحث پیش کی جاتی ہے۔
دیلمیؒ کی اول الذکر (یعنی حضرت علیؓ کی مرفوع) حدیث کی سند میں عبد الوہاب حضرت مجاہد بن جبر یعنی اپنے والد سے روایت کرتا ہے حالانکہ اس کا حضرت مجاہد سے سماع نہیں ہے۔ امام بخاریؒ اور وکیعؒ وغیرہ نے اس امر کی تصریح کی ہے۔ امام نسائیؒ اس کی نسبت فرماتے ہیں ’’متروک الحدیث ہے‘‘۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں ’’یحیٰیؒ کا قول ہے کہ اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی‘‘۔ عثمان بن سعیدؒ یحیٰی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ’’وہ کچھ بھی نہیں ہے‘‘۔ امام احمدؒ بھی فرماتے ہیں کہ ’’وہ کچھ بھی نہیں، ضعیف الحدیث ہے‘‘۔ ابن عدیؒ فرماتے ہیں کہ ’’جو کچھ وہ روایت کرتا ہے عموماً اس کی متابعت نہیں ہوا کرتی‘‘۔
’’عبد الوہاب بن مجاہد بن جبیر‘‘ کے تفصیلی ترجمہ کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ضعفاء الکبیر للبخاریؒ ضعفاء المتروکون للنسائیؒ، تاریخ یحیٰی بن معینؒ، سؤالات محمد بن عثمانؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ، ضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، جرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، مجروحین لابن حبانؒ، کامل فی الضعفاء لابن عدیؒ، ضعفاء والمتروکون للدارقطنیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، تہذیب التہذیب لابن حجرؒ اور مجموع فی الضعفاء والمتروکین للسیروان وغیرہ۔
حضرت علیؓ کی اس مرفوع حدیث کی تخریج ابن عساکرؒ نے بھی کی ہے جس کے متعلق علامہ سید ابو الوزیر احمد حسن دہلیؒ (م ۱۳۳۸ھ) فرماتے ہیں ’’اس باب میں ابن عساکرؒ نے بھی حضرت علیؓ سے باسناد حسن روایت کی ہے‘‘۔ اور علامہ شیخ عبد الرحمٰن مبارکپوریؒ فرماتے ہیں ’’اور ابن عساکرؒ نے بھی حضرت علیؓ سے اس کی تخریج کی ہے جیسا کہ جامع الصغیر میں مذکور ہے۔‘‘ علامہ منادیؒ فرماتے ہیں کہ ’’یہ حدیث باسناد حسن مروی ہے‘‘ (تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۳۸۳)۔ حالانکہ یہ حدیث سندًا ’’ضعیف‘‘ ہے جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے۔ غالباً صاحبان ’’تنقیح الرواۃ‘‘ و ’’تحفۃ الاحوذی‘‘ رحمہم اللہ کو علامہ منادیؒ کے قول سے وہم ہوا ہے۔ حضرت علیؓ کے طریق سے وارد ہونے والی اس حدیث کو علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے ’’ضعیف الجامع الصغیر و زیادتہ‘‘ میں وارد کیا ہے۔
دیلمیؒ اور عفیف الدین ابوالمعالیؒ کی روایت کردہ حدیث ’’ضعیف‘‘ نہیں بلکہ اصلاً ’’موضوع‘‘ ہے۔ اس روایت کو امام سیوطیؒ نے اپنی ’’جامع‘‘ اور ’’ذیل الاحادیث الموضوعہ‘‘ (للسیوطیؒ ص ۴۲) میں، امام النجارؒ نے اپنی ’’تاریخ‘‘ میں اور علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے ’’سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ (ج ۲ ص ۲۲۴۔۲۲۵) میں وارد کیا ہے۔ اس کی سند میں ابراہیم بن ہانی ’’مجہول‘‘ راوی ہے اور اگلے تین روای انتہائی مجروح بلکہ ’’متروک‘‘ ہیں۔
(۱) زیاد بن ابی حسان البصری جس کی نسبت امام حاکمؒ اور نقاش کا قول ہے کہ ’’وہ حضرت انسؓ وغیرہ سے موضوع احادیث بیان کرتا ہے‘‘۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں ’’شعبہؒ نے اس پر شدید جرح کی اور اس کی تکذیب کی ہے۔ دارقطنیؒ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ ابو حاتم الرازیؒ وغیرہ نے کہا کہ ’’اس کے ساتھ کوئی حجت نہیں ہے‘‘۔
ابن ابی حسان کے تفصیلی ترجمہ کے لیے تاریخ الکبیر للبخاریؒ، تاریخ الصغیر للبخاریؒ، ضعفاء الصغیر للبخاریؒ، ضعفاء والمتروکون للدارقطنیؒ، جرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، مجروحین لابن حبانؒ، کامل فی الضعفاء لابن عدیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، لسان المیزان لابن حجرؒ اور مجموع فی الضعفاء والمتروکین وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔
(۲) اس سند کا دوسرا راوی ’’بکر ابن خنیس القاضی‘‘ ہے جس کو امام نسائیؒ نے ’’ضعیف‘‘ گردانا ہے۔ دارقطنیؒ نے ’’متروک‘‘ قرار دیا ہے۔ ابن حبانؒ فرماتے ہیں ’’بصریین اور کوفیین سے اشیائے موضوعہ روایت کرتا ہے‘‘۔ امام ذہبیؒ فرماتے ہیں ’’ابن معینؒ کا ایک قول ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا قول ہے کہ ضعیف ہے اور تیسرا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے‘‘۔ ابوحاتمؒ کا قول ہے کہ ’’صلح ہے لیکن قوی نہیں ہے‘‘۔
ابن خنیس القاضی کے تفصیلی ترجمہ کے لیے تاریخ یحیٰی بن معینؒ، تاریخ الکبیر للبخاریؒ، معرفۃ والتاریخ للبسویؒ، ضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، جرح والتعدیل لابن عدیؒ، ضعفاء المتروکون للدارقطنیؒ، ضعفاء والمتروکون للنسائیؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، المغنی فی الضعفاء للذہبیؒ، اور مجموعہ فی الضعفاء والمتروکین للسیروان وغیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔
(۳) اس سند کا تیسرا مجروح راوی ’’عمرو بن حکام‘‘ ہے لیکن مذکورہ بالا دونوں راوی ہی اصلاً اس روایت کی آفت ہیں۔ عمرو بن حکام کو امام نسائیؒ نے ’’متروک الحدیث‘‘ کہا اور امام بخاریؒ نے اس کی تضعیف کی ہے۔ امام احمدؒ نے بھی اس کی حدیث کو ’’ترک‘‘ کیا ہے۔ ابن عدیؒ بیان کرتے ہیں کہ ’’عموماً وہ جو کچھ روایت کرتا ہے اس میں متابعت نہیں ہوتی لیکن باوجود ضعف کے اس کی حدیث لکھی جاتی ہے‘‘۔ امام ذہبیؒ نے ’’میزان‘‘ میں اس سے مروی چند منکر روایات بطور نمونہ نقل فرمائی ہیں۔
عمرو بن حکام کے تفصیلی ترجمہ کے لیے تاریخ الکبیر للبخاریؒ، ضعفاء الکبیر للعقیلیؒ، جرح والتعدیل لابن ابی حاتمؒ، مجروحین لابن حبانؒ، کامل فی الضعفاء لابن عدیؒ، ضعفاء والمتروکون للنسائیؒ، ضعفاء الصغیر للبخاریؒ، میزان الاعتدال للذہبیؒ، اور مجموع فی الضعفاء والمتروکین للسیروان وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔
علامہ منادیؒ اس حدیث پر تعف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں ’’اس کی سند میں ابراہیم بن ہانیؒ ہے جسے امام ذہبیؒ نے ’’الضعفاء‘‘ میں وارد کیا ہے اور کہا ہے کہ مجہول ہے اور بواطیل لاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے راوی عمرو بن حکام سے روایت کرتا ہے جسے امام احمدؒ اور نسائیؒ نے ترک کیا ہے اور عمرو بن حکام بکر بن خنیس سے روایت کرتا ہے جسے دارقطنیؒ نے متروک بتایا ہے، اور وہ زیاد بن ابی حسان سے روایت کرتا ہے اور اسے بھی ترک کیا گیا ہے۔
تعجب تو علامہ جلال الدین السیوطیؒ پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے دیلمیؒ کی اس حدیث کو اس کی تحقیق کے بغیر نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اپنی ’’الجامع‘‘ میں وارد کیا ہے اور پھر طرفۂ تماشہ یہ کہ اسی روایت کو اپنی ’’ذیل الاحادیث الموضوعہ‘‘ میں بھی لکھ ڈالا ہے۔
دیلمیؒ کی آخری دونوں روایتیں چونکہ بلاسند مروی ہیں، لہٰذا ازروئے اصولِ حدیث ان کے معیار کی تحقیق ممکن نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابن عمرؓ والی آخری حدیث کے مشابہ ایک قول حضرت علیؓ سے موقوفاً بھی مروی ہے جیسا کہ علامہ سخاویؒ اور علامہ عجلونیؒ وغیرہ نے بصراحت بیان کیا ہے۔
پس ثابت ہوا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اس کے جملہ طرق انتہائی ’’ضعیف‘‘ اور قطعاً غیر معتبر ہیں۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ علم و حکمت کے حصول کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ حکیمانہ قول ہمارے اسلاف و حکماء میں سے بعض کا ہو۔ علامہ سخاویؒ اور علامہ عجلونیؒ نے اس سلسلہ میں اسلافؒ کے کچھ اقوال بھی نقل کیے ہیں جو راقم کی اس رائے کے لیے شاہد و مؤید ہیں۔ ان میں سے کچھ اقوال اس طرح ہیں:
عسکریؒ نے سلیمان بن معاذ عن عکرمہ عن ابی عباس کے طریق سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول روایت کیا ہے:
خذ الحکمۃ ممن سمعت فان الرجل یتکلم بالحکمۃ ولیس بحکیم فتکون کالرمیۃ خرجت من غیر رام۔
بیہقیؒ نے سعید بن الجابردہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے:
الحکمۃ ضالۃ المؤمن یأخذ ھا حیث وجدھا۔
اور بیہقیؒ عبد العزیز بن ابی رواد کے حوالہ سے عبد اللہ بن عبید بن عمر کا یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں:
العلم ضالۃ المؤمن یغد و فی طلبھا فان اصاب منھا شیئاً حواہ حتٰی یصم الیہ غیرہ۔
خود عسکریؒ کا قول ہے:
اراد صلی اللہ علیہ وسلم ان الحکیم یطلب الحکمۃ ابدا وینشد ھا فھو بمنزلۃ المضل ناقتہ یطلبھا۔
علامہ ملا علی القاری حنفیؒ نے بھی اپنی ’’اسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ المعروف بالموضوعات الکبرٰی‘‘ میں اس حدیث کو وارد کرنے کے بعد اشارہ فرمایا ہے کہ (یہ بعض سلفؒ کا کلام ہے)۔ اگرچہ اسلافؒ کے مندرجہ بالا اقوال میں سے بھی اکثر سندًا معیارِ صحت پر بہت زیادہ پختہ اور قوی ثابت نہیں ہوتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی غیر مستند قول یا فعل کو منسوب کیا جانا بدرجہا مہلک ہے، بہ نسبت اس بات کے کہ سلف صالحین میں سے کسی کی جانب سے آنے والی کوئی غیر قوی خبر بیان کر دی جائے اور اسے شرعی دلیل کے طور پر نہ اپنایا جائے۔ واللہ اعلم۔
فقہی اختلافات کا پس منظر اور مسلمانوں کے لیے صحیح راہِ عمل
الاستاذ محمد امین درانی
فقہی اختلاف سے مراد شرعی احکام میں علماء امت کا وہ اختلاف رائے ہے کہ کون سا عمل زیادہ درست، زیادہ افضل اور بہتر ہے اور زیادہ مستند ہے۔ اہل السنۃ والجماعۃ کے چاروں مذاہب کا اختلاف بسا اوقات اس پر ہوتا ہے کہ کون سا کام اور کون سا طریقہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ ایک اسلامی عمل کو بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ وہ ہرگز ایسے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کریں یا اسے نیچے دکھانے مغلوب کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ دشمنانِ اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دین سے بے خبر سادہ لوح حضرات کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی پیدا کر کے اپنا مطلب حاصل کرتے ہیں۔ اس مصیبت کا اصل سبب دین اور دین کی تاریخ سے بے خبری اور جہل مرکب ہوتا ہے۔
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکایا گیا، وہ اس وقت کے مشہور علماء کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے اور جب ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کی وضاحت کی، امام جعفرؒ نے آپ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا بے شک آپ وہ ہستی ہیں جس نے میرے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو نشر کر کے اسے صحیح رنگ میں پیش کیا اور آپ کوئی نیا مذہب متعارف نہیں کراتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باحسن طریق لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔
فقہی اختلاف کی ابتدا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان سے دریافت کرتے اور حقیقت معلوم ہو جاتی اور اختلاف کی نوبت نہ آتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اٹل اور فیصلہ کُن ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہمیں اختلاف کی صورت نظر آتی ہے تو وہ ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے فہم کے مطابق ہے جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کا مطلب لیا ہے۔
مثلاً غزوہ بنی قریظہ کے لیے روانگی کے وقت فرمایا ’’کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے پاس پہنچنے کے بعد‘‘۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چل پڑے تو بعض نے اس حکم پر یوں عمل کیا کہ عصر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد راستہ میں نماز نہیں پڑھی اور بنو قریظہ کے علاقہ میں پہنچنے کے بعد نماز ادا کی۔ اور بعض نے اس حکم کا یوں مطلب لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم راستہ میں دیر نہ کریں اور انہوں نے راستہ میں عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فورًا بعد بنو قریظہ پہنچے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ڈانٹا۔
فقہی اختلاف کے اسباب
(۱) دعوتِ اسلام اور تبلیغ کے لیے اصحابِ رسولؐ کا مدینہ منورہ سے باہر جانا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کے مطابق احکام کا نزول ہوتا رہا۔ بعض اوقات یہ نوبت بھی آئی کہ ایک عمل کا حکم مثلاً نماز میں سینہ پر ہاتھ رکھنا نازل ہوا۔ ایک صحابیٔ رسول نے دیکھا کہ ہاتھ رکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ جب وہ تبلیغ کے لیے باہر گئے اور انہیں مدینہ سے باہر رہنا پڑا اور واپس آنا نصیب نہیں ہوا، وہ لوگوں کو وہی طریقہ یعنی سینہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیتے رہے۔
پہلا حکم تبدیل ہوا کہ نماز میں ہاتھ کھلا رکھنا ہے، باندھنا نہیں۔ جن اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب وہ تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے تو وہ لوگوں کو یہی درس دیتے تھے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا نہیں بلکہ کھلا چھوڑنا ہے۔ ان حضرات کو مدینہ منورہ واپس آنا نصیب نہیں ہوا اس لیے انہیں آخری حکم کا پتہ نہیں چل سکا، اور نہ وہ حضرات اس طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے جس طریقے پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔
اسی عمل کے بارے میں آخری حکم نازل ہوا کہ نماز میں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحابؓ جو نبوت کے آخری سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے انہوں نے نماز کا یہی طریقہ اپنایا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو عمر بھر اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور اس کے علاوہ اور کوئی کام کاج نہیں کیا، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے انہوں نے یہی طریقہ ہاتھ باندھنے کا کوفہ اور مدینہ میں لوگوں کو سکھایا۔
مجتہدین علماءِ امت میں سے ہر ایک نے اپنی تحقیق کے مطابق نماز میں ہاتھ رکھنے یا کھلا چھوڑ دینے کو اپنایا۔ امام ابوحنیفہؒ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے عمل کو افضل قرار دیا۔ جبکہ امام شافعیؒ اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبلؒ نے سینہ پر ہاتھ باندھنے کے عمل کو بہتر قرار دیا۔ اور امام مالکؒ نے ہاتھ کھلا رکھنے کو افضل اور بہتر فرمایا۔ ان ائمہ حضرات نے جس طریقے کو بہتر فرمایا، دوسرے طریقے کو ناجائز قرار نہیں دیا نہ اس کی ممانعت کی۔ کیونکہ یہ سارے طریقے ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابِ کرامؓ اور ان کے شاگردانِ عظام سے پہنچے۔ تو ایسا سمجھ لیجئے کہ ان ائمہ حضرات کے آراء ایک ہی درخت کے پھل ہیں اور وہ قرآن و سنت کا درخت ہے نہ کہ مختلف درختوں کے پھل ہیں جیسا کہ بے خبر لوگ وہم کرتے ہیں۔
(۲) قرآن و سنت کے کلمات (الفاظ) میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان عربی زبان میں نازل فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت بھی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معانی بھی ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب ایک معنی کی تعیین نہ ہو اور آسانی کی خاطر حکمتِ خداوندی نے ایسے لفظ کو استعمال کیا ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی اس لفظ کا ایک معنی لیں گے جبکہ دوسرے لوگ اس کے دوسرے معنی لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تعیین کے لیے کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے احکام کی توضیح وحی کے ذریعے ممکن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد یہ کام ناممکن ہو گیا کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔
(۳) فطری صلاحیت و استعداد کا تفاوت
حکمتِ خداوندی نے یہ چاہا کہ انسانوں کی فطری صلاحیت، عقل و فہم میں تفاوت ہو اور علم و عقل کے ذریعے ایک انسان کی دوسرے پر فضیلت ظاہر ہو۔ یہ واضح امر ہے کہ فطری استعداد، عقل و فہم اور علمی تفاوت کا نتیجہ اختلاف رائے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ایسے نصوص نازل کیے جن کے الفاظ ایک سے زیادہ معانی کا احتمال رکھتے ہیں، دوسری طرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فطری استعداد و صلاحیت سے نوازا۔ یہ دونوں فقہی اختلاف کے بنیادی اسباب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ تمام امت اس اختلاف سے دور رہے اور سب کی رائے خدائی احکام میں ایک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے کلمات ایسے منتخب کرتے کہ جن الفاظ کے صرف ایک معنی ہو اور تمام انسانوں کو ایک ہی قسم کی فطری صلاحیت اور ایک ہی معیار کے عقل سے نوازتے تاکہ تمام لوگ ایک مسئلے میں ایک ہی رائے والے ہوں۔ مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ’’وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِھِنَّ ثَلٰثَۃَ قُرُوْءٍ‘‘ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ تین قروء انتظار کریں گی۔ تین قروء عدت ہے۔ قروء، قرء کی جمع ہے۔ اہلِ عرب کے نزدیک قرء کا معنی حیض بھی ہے اور طہر (پاکی) بھی ہے۔ اور بعض اہلِ زبان قرء کا معنی ’’حیض مع طہر‘‘ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی تعیین نہیں ہو سکی کہ قرء سے مراد حیض ہے یا طہر۔ چنانچہ حضرت عمر، حضرت علی، عبد اللہ بن مسعود، ابو موسٰی اشعری، مجادہ، قتادہ، الضحاک، عکرمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے تابعین حضرات نے قرء کا مطلب حیض لیا۔ یعنی طلاق کے بعد جب عورت کو تین بار حیض سے واسطہ پڑے تو تیسرے حیض کے بعد وہ آزاد ہو گی، کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ ان جلیل القدر اصحاب کرامؓ اور بزرگ تابعین کی رائے کو امام ابوحنیفہؒ نے پسند کیا جب کہ دوسرے صحابہؓ حضرت عائشہ، عبد اللہ بن عمر، زید بن ثابت، ابن شہاب الزہری، امام شافعی رضوان اللہ علیہم نے قرء سے مراد طہر لیا۔ جب عورت کو طلاق کے بعد تین بار حیض اور تین بار پاکی (طہر) سے واسطہ پڑے تو چوتھی بار حیض کے دوران یا اس کے بعد وہ آزاد ہو گی اور کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ امت اس بارے میں مختلف نہ ہو تو وہ ایسا حکم نازل کر سکتے تھے ’’والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلٰثۃ شھور‘‘ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ تین ماہ انتظار کریں گی۔ ظاہر ہے کہ لفظ ’’شھر‘‘ کا معنی عربی زبان میں ایک ہے اور وہ ’’مہینہ‘‘ ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم ایسا بیان فرمایا ’’لِلَّذِیْنَ یُؤْلُوْنَ مِن نِّسَآءِھِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَۃَ اَشْھُر‘‘ جو لوگ عورتوں سے قسم کریں گے (کہ وہ ان کے قریب نہ ہوں گے) وہ چار ماہ انتظار کریں گے، چار ماہ کے بعد ایک طلاق واقع ہو گی۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر شہر کا لفظ ہے جس کے معنی ماہ یا مہینہ ہے۔ یہاں قرء جیسے مشترک المعنے لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا۔
اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ فقہی اختلاف حکمتِ خداوندی کے تحت ظہور میں آیا تاکہ انسان کے اوپر تنگی نہ ہو بلکہ فراخی ہو اور جیسے موقع اور حالات کے لحاظ سے سہولت ہو، اسی طریقے کو اپنا لیا جائے، انسان کی علمی اور عملی فطرت اس کے متقاضی ہیں۔
پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے فرمایا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ کے درمیان اختلاف نہ ہوتا کیونکہ اگر سب اصحابؓ کا ایک قول ہوتا تو لوگ تنگی میں ہوتے کیونکہ یہ اصحابؓ ہمارے رہنما ہیں اور ہمیں ان کی اقتداء کرنی ہے۔ اب جس شخص نے کسی صحابیؓ کے قول پر عمل کیا تو وہ حق پر ہے اور فراخی میں ہے۔ ابوبکر صدیقؓ کے جلیل القدر پوتے القاسمؒ بن محمدؓ سے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، اگر آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیا تو آپ نے اصحابؓ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی اور اگر آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھا تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ کی پیروی کی۔
چنانچہ مشہور حدیث شریف ہے ’’میرے ساتھی ستاروں کی مانند ہیں جس کی آپ نے پیروی کی آپ نے ہدایت پائی۔‘‘
اختلافی مسائل میں علماء کا موقف
اس بارے میں جمہور علماء متقدمین اور متاخرین کا یہ موقف رہا ہے کہ پہلے وہ ان کے بارے میں علم حاصل کرتے تھے، ان کے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہ کون سی بات پہلی ہے اور کونسا حکم بعد میں ہے۔ امام مالکؒ سے جب اس اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا ایک بات درست ہو گی اور دوسری خطا، آپ کو تحقیق کرنی چاہیئے۔ امام لیثؒ بن سعد فرماتے تھے، اختلاف میں ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں۔
امام ابوحنیفہؒ نے اس کا حل یوں کیا کہ اپنے چار ہزار سے اوپر شاگردوں سے اونچے درجے کے چالیس عالم منتخب کیے اور عالموں کی اس مجلسِ مشاورت و تحقیق کے لیے امام ابویوسفؒ کو سیکرٹری منتخب کیا۔ امام ابوحنیفہؒ نے اس مجلسِ تحقیق سے یوں فرمایا، ’’لوگوں نے مجھے دوزخ کے اوپر پل بنا دیا ہے، آپ میری مدد کریں، جو روایت زیادہ صحیح، قوی اور آخری ہو وہ معلوم کر کے مجلس میں پیش کیا کریں، منظوری کے بعد اسے لکھا جائے گا‘‘۔ امام ابوحنیفہؒ کوئی مسئلہ پیش کرتے اور ان چالیس علماء سے قرآن و حدیث سے دلیل مانگتے۔ وہ علماء دلائل پیش کرتے، کبھی کبھی ایک مہینہ تک ایک ہی حکم پر تحقیق ہوتی رہتی اور جب فیصلہ ہو جاتا تھا تو امام ابویوسفؒ کو لکھنے کے لیے حکم دیتے تھے۔ اس طریقِ کار سے امام ابوحنیفہؒ نے یہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے آخری عمل کون سا ہے جس کو اپنایا جائے اور منسوخ حکم معلوم ہو کہ اس کو ترک کر دیا جائے۔
اختلافی مسائل میں مسلمانوں کا آپس میں برتاؤ
صحابہ کرامؓ اور تابعین میں کچھ ایسے تھے جو نماز میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ جہر (زور) سے بسم اللہ پڑھتے تھے اور بعض آہستہ چپکے سے پڑھتے تھے۔ اور بعض فجر میں قنوت پڑھتے تھے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور دوسرے مجتہدین مدینہ منورہ کے علماء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جبکہ وہ نماز میں فاتحہ سے پہلے کبھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے نہ جہر سے نہ آہستہ۔
خلیفہ ہارون رشید نے نماز پڑھائی اور اس نے فصد کے ذریعے جسم سے خون نکالا تھا۔ خلیفہ کو امام مالکؒ نے فتوٰی دیا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ مذہب حنفی میں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابویوسفؒ مذہب حنفی کے مجتہد ہیں لیکن انہوں نے نماز نہیں لوٹائی۔
امام شافعیؒ کے نزدیک فجر میں قنوت پڑھنا ہے۔ ایک دن انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی قبر کے نزدیک (مسجد امام اعظم کے جنوبی جانب میں امام اعظمؒ کی قبر ہے) فجر کی نماز پڑھی اور قنوت کی دعا نہیں پڑھی امام ابوحنیفہؒ کے ادب کی وجہ سے اور کہا کہ بسا اوقات ہم عراقی مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
خلیفہ ہارون رشیدؒ نے امام مالک سے کہا میں آپ کی کتابِ حدیث ’’المؤطا‘‘ کو کعبہ میں لٹکاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ صرف ان روایات پر عمل کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ نے فروعی مسائل میں اختلاف کیا اور مختلف ملکوں میں چلے گئے اور ہر ایک حکمِ رسولؐ نافذ ہے (کسی کو پابند نہیں کرنا چاہیئے)۔ خلیفہ ہارون الرشیدؒ کو یہ بات پسند آئی۔ اس سے پہلے خلیفہ منصور کے ساتھ بھی امام مالکؒ کا یہی قول تھا۔
اس تمام بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ فقہی اختلافی مسائل میں جو روایت زیادہ مستند اور قوی ہو اس کو ترجیح دی جائے۔ ائمہ اربعہ بالخصوص امام ابوحنیفہؒ کی تحقیق سے استفادہ کیا جائے اور ظاہر الروایۃ کے مسائل کو ترجیح دی جائے۔ ان کے خلاف مسائل کو بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ وسیع القلبی سے کام لے کر تمام مذاہب اہل سنۃ کے پیروکاروں کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ لیا جائے اور ان کے ساتھ بحث و مناظرہ سے اجتناب کیا جائے۔ سب ہی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، اپنے ملک کے اندر بھی مسجد حرام اور مسجد نبویؐ جیسا منظر پیش کرنے کی کوشش کریں جہاں تمام مذاہب کے لوگ حنبلی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے درمیان جو دشمنانِ اسلام نے نفرت و تعصب کو ابھارا ہے اس کو خیرباد کہہ کر اسلامی اخوت کا منظر پیش کریں۔
علمِ نباتات کے اسلامی ماہرین (۱)
قاضی محمد رویس خان ایوبی
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے جہاں انسانی اخلاقیات، تہذیب و تمدن، عقیدۂ توحید اور حیات اخروی، انسانی جان و مال، عقیدہ و دین، عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے قوانین وضع کر کے ایک مکمل اسلامی ریاست کے خدوخال واضح کیے ہیں، وہیں پیروکارانِ اسلام نے قرآن کریم کے عمیق مطالعہ سے ایسے نئے نئے علوم دریافت کیے جو یورپ کے حاشیۂ خیال میں بھی نہ تھے۔ ’’وَاَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِح‘‘ قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ نقطۂ نظر علماءِ سائنس کے سامنے پیش کیا کہ درختوں میں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ قائم ہے۔
اسلام چونکہ سب سے پہلے عربوں میں آیا اور اس کے اولین مخاطب عرب تھے اس لیے عربوں نے علمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عربوں میں یوں تو جڑی بوٹیوں کی تحقیق کا سلسلہ عرصۂ دراز سے جاری تھا، وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے اور انہیں جڑی بوٹیوں کے خواص معلوم تھے، باقاعدہ تحقیقی کام دوسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ مسلمان محققین نے علمِ نباتات کو باقاعدہ بنانے کے لیے باقاعدہ ڈکشنریاں مرتب کیں اور علمِ نباتات کے سلسلے میں مختلف درختوں، ان کی خصوصیات، جڑی بوٹیوں کی فہرست اور ان کے مختلف اسماء پرمشتمل نصاب مرتب کیں۔ان محققین میں ابو عبیدہ قاسم بن سلام (المتوفی ۸۳۷م)، سعید بن اوس انصاری (متوفی ۸۳۰م) اور عبد المالک الاصمعی (متوفی ۸۳۱م) قابل ذکر ہیں۔
آج کی نشست میں ہم قارئین کے لیے ان مشہور و معروف محققینِ نباتات کا مختصر سوانحی خاکہ پیش کر رہے ہیں جن کی خدمات جلیلہ سے اہلِ یورپ نے فائدہ اٹھا کر دنیائے طب و علمِ نباتات میں نام پیدا کیا اور ہماری کتب چرا کر اپنے دیے جلائے اور مسلمانوں کا نام دنیا کی انسائیکلوپیڈیا سے غائب کر دیا۔
(۱) ابو العباس احمد بن محمد بن مفرج النباتی المعروف ابن الرومیہ
آپ ۱۱۶۵ میلادی میں اشبیلہ میں پیدا ہوئے۔ گھومنے پھرنے کا شوق ابتداء سے ہی تھا، اسی شوق نے انہیں مشرق و مغرب میں تحقیقی سفر اختیار کرنے پر مجبور کیا اور مختلف درختوں کا مشاہدہ کیا، ان کا خالص نباتاتی نقطۂ نظر سے مطالعہ کیا۔ اس طرح انہوں نے مختلف درختوں کی شاخوں، تنے، جڑوں، پھولوں کے خواص معلوم کیے۔ انہوں نے ہسپانیہ، شمالی افریقہ، مصر، حجاز، عراق اور شام کا سفر کیا اور ’’کتاب الرحلۃ‘‘ کے نام سے اپنا سفرنامہ تصنیف کیا جس میں ان درختوں کا ذکر اور خواص بیان کیے گئے ہیں جن کا انہوں نے دورانِ سفر مشاہدہ کیا۔ اس نے بحر قلزم کے کنارے اگنے والی بعض جڑی بوٹیوں کے خواص معلوم کیے جن کا اس وقت تک کسی کو علم نہ تھا۔ اختتامِ سفر پر اس نے اشبیلہ میں پنسار کی دکان کھولی۔ ابن ابار کہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام ہم عصروں میں سب سے زیادہ لائق اور ماہر عالم تھا۔
تصانیف
احمد بن محمد نے علمی اثار میں اپنی حسب ذیل تصانیف چھوڑیں جو علم کا خزینہ ہیں:
(۱) کتاب الرحلۃ۔ سفرنامہ
(۲) تفسیر اسماء الادویۃ المفردۃ من کتاب دیستوریدس۔ اس کتاب میں مصنف نے مفرد جڑی بوٹیوں کے خواص بیان کیے ہیں۔
(۳) مکالمہ فی ترکیب الادویہ۔ مرکب ادویات بنانے کا طریقہ۔
(۴) ادویۃ جالینوس المستدرکۃ۔ یہ کتب بھی مختلف دواؤں کی خصوصیات سے متعلق ہیں۔
وفات
تاریخ اسلام کا یہ عظیم فرزند ۱۲۳۹م میں اشبیلہ میں داعیٔ اجل کو لبیک کہا اور وہیں دفن ہوا۔
(۲) ابو جعفر احمد بن محمد الغافقی
ہسپانیہ کا یہ عظیم فرزند جس کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہو سکے، بہرحال یہ عظیم فرزند بھی نباتات کا عالم تھا، اس نے ’’الادویہ المفردہ‘‘ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے ادویہ کی خصوصیات تحریر کیں۔ اس نے اس تصنیف میں دیستوریدس اور جالینوس کی کتب سے استفادہ کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں ادویہ کے نام عربی، لاطینی اور بربری زبان میں دیے۔ اس کی کتاب کی تلخیص ابوالفرج السوری ابن العربی نے ’’جامع المفردات‘‘ کے نام سے لکھی جو ۱۹۳۰م میں قاہرہ میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ غافقی نے بخار و تپ دق کے بارے میں بھی ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ’’رسالۃ الحمیات والمروق‘‘ رکھا۔
وفات
اشبیلہ میں وفات پائی، صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی البتہ سنِ میلادی ۱۱۶۵ تھا۔
(جاری)
’’اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی‘‘
مولانا سراج نعمانی
خطیبِ شہیر مولانا حق نواز صاحب بھی شہید کر دیے گئے۔ آخر کیوں؟ اخبارات نے اس موضوع پر کالم لکھے، اداریے لکھے، مضامین اور خبروں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ ماہنامہ اور ہفت روزہ رسائل میں تبصری، تجزیے اور اندازے تحریر ہو رہے ہیں۔ اس مضمون کی اشاعت تک لاہور میں عظیم الشان دفاعِ صحابہؓ کانفرنس اور تعزیتی احتجاجی جلسہ بھی منعقد ہو چکا ہو گا جس میں جانشین امیر عزیمت مولانا ضیاء الرحمٰن فاروقی اپنی مستقبل کی پالیسیوں کی نشاندہی بھی کر چکے ہوں گے۔
لیکن ان تمام تر تجزیوں، تبصروں، تحریروں اور تقریروں کے باوجود مولانا حق نواز شہید کی اس شہادت سے کیا ہم نے کچھ سبق لیا ہے؟ کیا ہمارے کردار اور گفتار میں موافقت پیدا ہو چکی ہے؟ کیا اب وہ مقاصد ہمیں آنکھیں بند کیے حاصل ہو جائیں گے جو مولانا شہید کے پیشِ نظر تھے؟ یا ہم اسی طرح حکمِ قرآنی کی مخالفت میں اندھے اور بہرے ہو کر ہر ناحق کو سجدے کرتے رہیں گے؟ کیا ان ظالم طاغوتی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں اب ختم ہو جائیں گی جن کے ایما پر مولانا شہید کیے گئے۔ کیا ان طاغوتی اور شیطانی لشکروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اس ملک میں علماء اور قائدین کے قتل عام کی چھٹی دے دی ہے؟
لیکن ہماری سطحی نظریں اس پس منظر کو کیسے پہچانیں جس پس منظر کو فراستِ ایمانی سے جانچا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ’’اِتَّقُوْا فَرَاسَۃِ الْمُؤْمِنِ لِاَنَّہٗ یَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰہِ‘‘ (طبرانی) مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نورِ ہدایت سے دیکھتا ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ ’’قُلُوْبُنَا فِیْ اَکِنَّۃٍ وَّفِیْ اٰذَانِنَا وَقْر‘‘ ہمارے دل غلافوں میں بند ہو چکے ہیں اس لیے کچھ سوچتے نہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں کسی اور کی نصیحت بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ شاید ہماری ہی حالت کے پیش نظر سابقہ امتوں کی حالت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی:
لَھُمْ قُلُوْبُ لَّا یَفْقَھُوْنَ بِھَا وَلَھُمْ اٰذَانٌ لَّا یَسْمَعُوْنَ بِھَا وَلَھُمْ اَعْیُنٌ لَّا یُبْصِرُوْنَ بِھَا اُولٰئِکَ کَالْاَنْعَامِ بَلْ ھُمْ اَضَلّ۔
یقیناً آج ہماری یہی حالت ہے مگر اس ذلت کا اقرار کرتے ہوئے شرماتے ہیں، جھجھکتے ہیں، نہیں تو سوچئے کہ کیا سوئے ہوئے شخص کو بیدار کرنے کے لیے چند آوازیں کافی نہیں؟ اگر کوئی ہوش و خرد سے بھی بیگانہ ہو کر سو جائے تو اس کو بھی جھنجھوڑ کر بیدار کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری بدقسمت قوم! آہ ’’اَمْ عَلیٰ قُلُوْبٍ اَقْفَالُھَا‘‘ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں کہ اتنے عظیم حادثات پے در پے ظہور پذیر ہو رہے ہیں مگر سوائے احتجاجی جلسوں، جلوسوں اور قراردادوں کے کیا ہوا؟ ’’لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ؟‘‘ کہاں جلسوں اور جلوسوں میں بلند بانگ دعوے اور کہاں جیل کی کوٹھڑی میں چند راتیں گزارنے کے بعد بھیگی بلیاں ’’وَاَنَّھُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا‘‘۔
اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مولانا کیوں شہید کیے گئے؟ شیطانی طاقتیں جب بھی نیکی کی قوتوں کو بیدار ہوتا دیکھتی ہیں تو وہ اپنا طریق کار چار مراحل میں تقسیم کر کے اس کا راستہ روکتی ہیں۔
پہلا مرحلہ
طعن و تشنیع اور بے عزتی کا ہوتا ہے جس مرحلے میں شیطانی طاقتیں حق پرستوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتی ہیں اور حق پرستوں کی اہمیت اور وجود کو زائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مختلف القابات اور طعن آمیز گفتگو سے حق پرست طاقت کو ابھرنے سے روکا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ’’سَاحِرٍ اَوْ مَجْنُوْن‘‘ اور کبھی کہتے ہیں ’’مَا لِھٰذَا الرَّسُوْلِ یَاْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِیْ فِی الْاَسْوَاق‘‘ اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ’’اَھٰذَا بَعَثَ اللّٰہُ رَسُوْلًا‘‘ کیا خدا کو اور کوئی نہیں ملتا تھا کہ اسے ہی پیغامبر بنا دیا۔
دوسرا مرحلہ
پھر سودا بازی ہوتی ہے کہ نہ تم ہمیں برا کہو اور نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے۔ اگر آپؐ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی حسین ترین لڑکی سے شادی کرا دیں گے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت کے انبار لگا کر آپ کو دے دیں گے۔ اور اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپؐ کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ بشرطیکہ آپ ہمارے خلاف ہونے والا پروگرام ختم کر دیں۔ لیکن امام الرسلؐ جنہوں نے تمام انبیاءؑ سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں انہوں نے قیامت تک کے لیے مثال پیش کر دی کہ اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے اعلانِ حق سے باز نہ آؤں گا۔ فرعون نے بھی سودا بازی کرتے ہوئے کہا تھا ’’اِنَّکُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبُوْن‘‘۔
تیسرا مرحلہ
علاقہ بدری اور سوشل بائیکاٹ کا ہوتا ہے۔ ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ داعیٔ حق ہجرت پر مجبور ہو جائے، یا شعبِ ابی طالب میں نظربند ہو جائے۔ اور صرف اسی پر ہی بس نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کے کردار کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے ہر ممکن حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طعن و تشنیع کے جن طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے انہیں صرف زبانی حد تک ہی اس مرحلے میں نہیں چھوڑا جاتا بلکہ کبھی تو ان کے پیغام سے دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ’’لَا تَسْمَعُوْا لِھٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِیْہِ لَعَلَّکُمْ تَغْلِبُوْنَ‘‘ اور کبھی ’’اِنَّھُمْ اُنَاسٌ یَّتَطَھَّرُوْنَ‘‘ کہتے ہوئے سرِعام انکارِ حق کر دیا جاتا ہے۔ اسی مرحلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے ’’مَتٰی ھٰذَا الْوَعْدُ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ‘‘۔
چوتھا مرحلہ
آخری مرحلہ ہوتا ہے جہاں باطل کے تمام ہتھکنڈے اور حربے ختم ہو جاتے ہیں۔ حق پرستوں کو دبانے اور ختم کرنے سے عاجز آ کر کبھی ’’حَرِّقُوْہُ وَانْصُرُوْا اٰلِھَتَکُمْ‘‘ کے فتوے داغے جاتے ہیں اور کبھی ’’لَاُصَلِّبَنَّکُمْ اَجْمَعِیْن‘‘ کا ورد کیا جاتا ہے اور کہیں ’’لَئِن لَّمْ تَنْتَھُوْا لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَلَیَمَسَّنَّکُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْمٌ‘‘ کی مالا جپی جاتی ہے۔ ہر ماحول اور ہر معاشرے نے اپنے اپنے حالات کے مطابق داعیانِ حق کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے نت نئے ہتھکنڈے ایجاد کیے جن کا نقطۂ اختتام موت یا شہادت ہوتا ہے لیکن وہ شاید نہیں سمجھتے کہ شہید آخری وقت میں بھی اعلانِ حق سے باز نہیں رہتا اور کبھی کہتا ہے ’’فَزْتُ بِرَبِّ الْکَعْبَۃِ‘‘ اور کبھی کہتا ہے ’’یٰلَیْتَ قَوْمِیْ یَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِیْ رَبِّیْ وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْمُکْرَمِیْنَ‘‘ قیامت کے دن تو باطل پرستوں سے پوچھ گچھ ہو گی لیکن ہم اس دنیا میں بھی ’’بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ‘‘کی آواز بلند کرتے ہوئے کہیں گے ’’وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیٰوۃٌ یَّا اُولِی الْاَلْبَابِ‘‘۔
مولانا حق نواز کی شہادت کوئی وقتی اشتعال کا نتیجہ نہ تھا وہ یقیناً ان چاروں مراحل سے گزر گئے لیکن مولانا کی یہ حق گوئی ان وارثانِ علومِ نبوت کا شیوہ تھی جس کا ایک تاریخی تسلسل دنیا میں موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ میں ہی اسی تسلسل کو اجمالی نگاہ سے ملاحظہ کریں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا اعلانِ حق یزید کے سامنے، حضرت سعید بن جبیرؓ کا اعلانِ حق حجاج بن یوسف کے سامنے، امام اعظمؒ کا اعلانِ حق منصور کے سامنے، امام احمد بن حنبلؒ کا اعلانِ حق معتصم باللہ کے سامنے، برصغیر میں امام ربانیؒ کا اعلانِ حق دربارِ جہانگیری میں، شاہ عبد العزیز دہلویؒ کا اعلانِ حق کہ ہندوستان دارالحرب ہے، انگریز کے خلاف علماء ہند کا جہادِ آزادی بالاکوٹ کے مقام تک، ۱۸۵۷ء میں دوبارہ جنگِ آزادی، دارالعلوم دیوبند کا قیام، شیخ الہندؒ کا کردار، اسی طرح مفتی کفایت اللہ دہلویؒ، مولانا سیوہارویؒ، مولانا مدنیؒ، مولانا عبید اللہ سندھیؒ، مولانا احمد سعید دہلویؒ اور ان کے بعد حضرت لاہوریؒ اور مولانا غلام غوث ہزارویؒ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غلبۂ دین کی خاطر انہوں نے اپنے اور پرائے کی تمیز کیے بغیر ظالم کے ظلم کو للکارا اور حق کا اعلان کر کے اس فریضہ سے سبکدوش ہوئے جو بحیثیت اہل الذکر ان پر عائد تھی۔ ’’فَاسْئَلُوْا اَھْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ‘‘۔
آخری گزارش علماء حق سے یہی کی جا سکتی ہے کہ فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ’’اَلسَّاکِتْ عَنِ الْحَقِّ شَیْطَانٌ اَخْرَسٌ‘‘ اور ’’مَنْ کَتَمَ عِلْمٍ عِنْدَہٗ اَلْجِمَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ‘‘۔ تو خدا کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں اور متحد اور متفق ہو کر شیطانی قوتوں سے ٹکر لے کر اس دنیا میں نظامِ خلافت کو دوبارہ زندہ کریں ’’وگرنہ داستاں تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں‘‘۔ تاکہ آئندہ کے لیے کسی شیطانی قوت کو پنپنے کے لیے کوئی کونا کھدرا بھی نہ مل سکے جہاں وہ چھپ سکیں اور دنیا میں دینِ حق اسلام کا بول بالا ہو ’’وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ‘‘۔
مسیحی ماہنامہ ’’کلامِ حق‘‘ کی بے بسی
حافظ محمد عمار خان ناصر
گوجرانوالہ سے شائع ہونے والا مسیحی ماہنامہ ’’کلامِ حق‘‘ ملقب بہ ’’راسخ الاعتقاد مسیحیت کا واحد علمبردار‘‘ (بابت ماہ فروری ۱۹۹۰ء) رقم طراز ہے:
’’الشریعۃ ماہنامہ میں آپ کے آرٹیکل سے حیرت ضرور ہوئی ہے اس لیے کہ اب خود اسلام کے اندر دشمنِ اسلام و قرآن اور منکرِ عقائد ایمان مفصل پیدا ہو رہے ہیں اور سابقہ علماء پر اسلام کے تراجم قرآن اور دلائل و براہین کے دشمن اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں ۔۔۔۔ اب ایک حافظ محمد عمار خان ناصر صاحب گوجرانوالہ میں پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی ان آیات کے منکر ہو گئے ہیں جو سابقہ الہامی کتب توریت اور زبور اور صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس کی تصدیق میں ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے جزوِ ایمان کا ستونِ اعظم ہے۔
حافظ صاحب کا یہ دعوٰی توہینِ قرآن میں شامل ہے اور وہ قرآن مجید سے اپنے دعوٰی کی تصدیق کے لیے کوئی آیت پیش نہیں کر سکتے۔ کتاب مقدس کی صداقت اور الہامی عظمت کے بارے اور مقابلہ میں یہ ان کی شکست خوردہ ذہنیت ہے۔‘‘ (ص ۱۶)
یاد رہے کہ یہ مضمون ’’پادری برکت اے خان آف سیالکوٹ‘‘ کا تحریر کیا ہوا ہے۔ اس ساری دل جلی عبارت کا لب لباب یہ ہے کہ ’’حافظ صاحب‘‘ نے بائبل کے ازروئے قرآن سچا اور الہامی ہونے کے دعوٰی کے ڈھول کا پول کیوں کھول کر رکھ دیا ہے؟ اور پادری صاحب کو یہ دلسوزی اس لیے کرنی پڑی کہ ’’حافظ صاحب‘‘ نے خود انہی کے حوالوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن نے جس توریت و انجیل کی تصدیق کی ہے، موجودہ مختلف و متضاد تحریفات کے پلندہ اناجیل اربعہ کو اس اصلی اور سچی انجیل سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ ہم اسی بحث کو یہاں نئے پیرائے میں دہرا رہے ہیں۔
اصولِ تنزیل میں فرق
پادری برکت اے خان لکھتے ہیں:
’’تمام مذاہب کے درمیان اختلافات کی دو بڑی اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تصوراتِ خدا ہے اور دوسری وجہ نزولِ الہامِ الٰہی ہے۔‘‘ (رسالہ اصول تنزیل الکتاب ص ۳)
مزید لکھتے ہیں:
’’مسیحیوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ توریت کی کتاب آسمان پر کسی خاص زبان میں آسمانی ورقوں پر خدا نے لکھ کر رکھی تھی۔ اسی طرح تمام پاک نوشتوں یعنی زبور کی کتاب، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس کے بارے میں بھی ہمارا ایسا ہی عقیدہ ہے۔‘‘ (ایضاً ص۳)
’’جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسٰی پر توریت شریف ایک کتاب کی صورت میں آسمان سے نازل ہوئی تھی ان کی یہ بات خداوند کی کتاب مقدس کے اصولِ الہام کے سراسر خلاف ہے کیونکہ آسمان پر پہلے سے توریت کی کتاب کی موجودگی کو تسلیم کرنے کے بعد ہی اس توریت کی کتاب کے بزرگ موسٰی پر آسمان سے نزول کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح زبور اور صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس کے متعلق بھی ان کے خیالات خداوند کی کتاب مقدس کے اصول الہام الٰہی کے سراسر منافی ہیں ۔۔۔۔
آسمان پر الہامی کتابوں کی موجودگی اور ان کی آیات کے لفظ بلفظ کسی خاص زبان میں نزول کا جو عقیدہ اہلِ اسلام کے درمیان مروج ہے، کتابِ مقدس کے صحائف کے متعلق نہ یہودیوں میں اور نہ مسیحیوں میں ایسا عقیدہ کبھی مروج ہوا ہے اور نہ انبیاء کرام خدا کی طرف سے وحی و الہام پا کر بصورتِ املا نویس محرر تھے۔‘‘ (ص ۶۰۵)
’’چنانچہ کتاب مقدس کے انبیاء کرام پر کلامِ الٰہی کی باتوں کے الہام و مکاشفہ کی صورت میں نزول کا طریقہ و عقیدہ میں اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اوپر ایک عجیب حالت و کیفیت میں نزول وحی قرآن کے طریقہ و عقیدہ میں بھی بڑا خاص فرق پایا جاتا ہے۔‘‘ ( ص ۱۰)
’’اگر قرآن مجید اور توریت شریف اور زبور شریف اور صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس ایک آسمان اور ایک ہی خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھیں تو پھر قرآن مجید نے باقی تمام الہامی کتابوں کی بعض ضروری ضروری باتوں اور اہم تعلیمات کے بارے میں اختلافی تعلیم کیوں پیش کی؟‘‘ (ص ۱۳)
قرآن پاک کا ساتویں صدی عیسوی کے گمراہی و ضلالت سے مرقع دور میں جب مسیحیوں کو دنیا کی سپرپاور کی حیثیت حاصل تھی ان کتبِ موضوعہ کے برخلاف تعلیم دینا ایک معجزہ اور صداقت کی نشانی تھا جسے پادری صاحب نے شرح صدر تسلیم کیا ہے۔ البتہ مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ امر اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اہل کتاب اور اہل اسلام کے درمیان الہام الہامی کے نزول کے اصول مختلف ہیں بلکہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی آسمان اور ایک ہی خدا کی جانب سے نازل شدہ نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن نے موجودہ تورات و انجیل کی تصدیق بھی نہیں کی اور پادری صاحب بیک وقت دو متضاد باتیں کہہ رہے ہیں۔
مقام حیرت و استعجاب ہے۔۔۔ پادری صاحب کو چاہیئے تھا کہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کی بجائے ہمارے ناقابلِ تردید دلائل کا توڑ پیش کرتے ۔۔۔ (۱) دشمنِ اسلام و قرآن (۲) منکرِ عقائد ایمان مفصل (۳) علماء اسلام کی تعلیمات کا دشمن (۴) قرآن مجید کی آیات کا منکر (۵) موہنِ قرآن (۶) شکست خوردہ ذہنیت (۷) بے شعور (۸) بدتمیز اور (۹) بدزبان جیسے القابات دینے کی بجائے کوئی دلیل کی بات کریں ۔۔۔ مزید برآں ’’کلامِ حق‘‘ کے مدیر صاحب کا یہ ارشاد بھی قابل توجہ ہے کہ ’’کلامِ حق کے مدیر نے حافظ صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے مفروضات کا جواب دیا جائے‘‘۔ حقیقت یہ ہے کہ خود پادری صاحب میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے ’’مفروضات‘‘ کا دفاع کر سکیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے خیالات پر کی گئی تنقید کا خود سامنا کرنے کی بجائے پادری برکت صاحب کو آگے کر دیا ہے اور یہی ان کی قابلیت ہے۔
بابری مسجد اور اجودھیا - تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش
دیوبند ٹائمز
آج کل بابری مسجد رام جنم بھومی کا جو قضیہ چلا ہوا ہے وہ عقائد، اقتدار اور سیاسی مسائل کا مظہر ہے۔ بلاشبہ ہر شخص کو اپنے عقائد اور یقین کے معاملہ میں پوری آزادی حاصل ہے لیکن جب عقائد تاریخ پر غالب آنے لگیں تو مؤرخ کو تاریخ اور عقائد کے درمیان حد قائم کرنی پڑتی ہے۔ فرقہ وارانہ سیاست کے مقصد سے جب فرقہ وارانہ قوتیں تاریخی شہادتوں پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں تو لامحالہ مؤرخ کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ تاریخی شہادت پیش کرنے کا مقصد اس قضیہ کو سلجھانے کے لیے کوئی حل پیش کرنا نہیں ہے کیونکہ اس جھگڑے کا تعلق تاریخی شہادتوں سے نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی سیاست کی فرقہ وارانہ سمتوں سے متعلق ہے، البتہ اس سلسلے میں تاریخی شواہد پیش کرنا پھر بھی ضروری ہے۔
سوال یہ ہے کہ بھگوان رام کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ کیا یہ اجودھیا میں ہے؟ دوسرے کیا آج جو اجودھیا ہے وہی وہ مقام ہے جو رامائن کے زمانے کا تھا۔ بھگوان رام کے قصوں کا ماخذ رام کتھا ہے جو آج میسر نہیں ہے۔ اسے دوبارہ رزمیہ نظم کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح والمیکی نے رامائن لکھی۔ نظم ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سی باتیں روایت اور قصے کی شکل میں داخل ہو گئی ہیں۔ بہت سے کردار اور مقامات بھی اسی طرح در آئے ہیں جیسا کہ کسی قصے کے بیان کرنے میں بہت سی باتیں فرضی ہو جاتی ہیں۔ تاریخ داں ان قصوں کے معتبر ہونے پر اس وقت تک شبہ کرتے رہیں گے جب تک کہ دیگر تاریخی حقائق سے ان کا ثبوت نہ مل جائے۔ والمیکی رامائن کے مطابق اجودھیا کے راجہ رام نے ترتیایگ جنم لیا۔ کالی یگ سے ہزاروں سال پیشتر کا ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ۱۰۲ ق م میں شروع ہوا تھا۔ ایسی کوئی تاریخی شہادت نہیں کہ اس زمانہ میں یہ اجودھیا (جیسا کہ یہ اب ہے) یہاں آباد تھا جہاں آٹھویں صدی ق م میں آباد ہوئی۔ والمیکی رامائن میں زندگی کے جو آثار ملتے ہیں وہ اس اجودھیا کے ساتھ آثار سے میل نہیں کھاتے۔
ظاہر ہے کہ والمیکی رامائن میں جس مقام کا ذکر ہے وہ یہ نہیں ہے جو کہ آج کا اجودھیا ہے۔ پھر اجودھیا کی جائے وقوع کے بارے میں بھی اختلاف رائے ہے۔ ابتدائی دور کی بودھ کتابوں میں شرادستی اور ساکیت کا ذکر ہے مگر اجودھیا کا نہیں۔ جین دھرم کی مذہبی کتابوں میں بھی کوسلہ کی راجدھانی ساکیت بتائی گئی ہے۔ اجودھیا کا ذکر نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اجودھیا گنگا کے کنارے آباد تھا نہ کہ دریائے سرجو کے کنارے جہاں آج کل اجودھیا ہے۔ ساکیت کا نام بدل کر گپت بادشاہوں نے اجودھیا رکھا۔ سکندر گپت نے یہ پانچویں صدی عیسوی کے آخر میں رہائش ساکیت میں بدل دی اور اسے اجودھیا کا نام دیا۔ اس وکرمادتیہ کا نام اختیار کیا جسے اس نے سونے کے سکوں پر استعمال کیا۔ اس طرح رزمیہ میں جس اجودھیا کا ذکر ہے وہ بہت بعد میں ساکیت سے اجودھیا بنا۔ اس سے یہ بھی واضح نہیں کہ گپت بادشاہ رام کے بھگت تھے۔ رام کا تعلق سوریہ دنش سے تھا۔ چنانچہ ساکیت کو اجودھیا کا نام دینے کا مقصد یہ تھا کہ سوریہ دنش خاندان سے خود کو متعلق کر کے اپنا وقار بلند کیا جائے۔
ساتویں صدی کے بعد رامائن میں اجودھیا کو کوسل کی راجدھانی بتایا گیا۔ اجودھیا ترتیایگ کے بعد گم ہو گیا تھا اور وکرمادتیہ نے اس کا دوبارہ سے پتہ چلایا۔ گمشدہ اجودھیا کی بازیافت کی کوشش میں وکرمادتیہ نے پیاگ سے ملاقات کی جو کہ تیرتھ کا بادشاہ تھا جو اجودھیا کے بارے میں واقف تھا۔ وکرمادتیہ نے اس جگہ کی نشان دہی کر دی تھی لیکن اس کے بعد میں پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد وہ ایک جوگی سے ملا جس نے کہا کہ اسے ایک گائے چھوڑ دینی چاہیئے اور اس کے ساتھ ایک بچھیا ہونی چاہیئے۔ یہ گائے اور بچھیا گھومتے رہیں۔ جب یہ رام جنم بھومی پر پہنچیں گے تو اس کے تھنوں سے دودھ ٹپکے گا۔ بادشاہ نے جوگی کی نصیحت مان لی۔ جب ایک مقام پر بچھیا نے دودھ ٹپکایا تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہی قدیم اجودھیا ہے۔ یہ ہے کہانی اجودھیا کی بازیافت کی۔
آج کا اجودھیا ساکیت کے نام سے مشہور رہا ہے۔ یہ مختلف مذہبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں محض رام کے ہی بھگت نہ تھے بلکہ یہ رام کی پوجا سے بہت بعد میں مخصوص کر دیا گیا۔ پانچویں صدی عیسوی سے آٹھویں صدی عیسوی تک اور بعد تک کتبوں پر اجودھیا کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ جگہ رام کی پوجا کے لیے مخصوص ہو (جیسا کہ ایپی گرافیکا انڈیکا ۱۰ میں صفحہ ۷۲ پر واضح کیا گیا ہے، اس کے صفحات ۱۵، ۱۴۳ اور صفحہ ۱۴ پر بھی اس کا حوالہ ملتا ہے)۔ ہیونگ سانگ نے اجودھیا بدھ مت کا زبردست مرکز بتایا ہے اور بودھ ستوپ، مٹھ یہاں بکثرت تھے۔ کچھ غیر بدھ لوگ بھی یہاں آباد تھے۔ بودھ اس مقام کو متبرک مانتے ہیں۔ یہاں مہاتما بودھ نے چند روز قیام کیا تھا۔ اجودھیا جینوں کا بھی متبرک اور مقدس مقام رہا ہے۔ جینیوں کا پہلے اور چوتھے تیرتھنکر یہیں پیدا ہوئے۔
گیارہویں صدی کی کتابوں میں اجودھیا میں گویاترو کا ذکر ملتا ہے لیکن رام جنم بھومی نہیں کہا گیا، یا رام جنم بھومی سے اس کا رشتہ نہیں جوڑا گیا۔ تیرہویں صدی عیسوی سے رام کی پوجا کرنے والے فرقے کومقبولیت ملی۔ رامانندی فرقے کے عروج سے اس کا ارتقا وابستہ ہے۔ ہندی میں رام کی کہانی تشکیل دی گئی۔ پندرہویں اور سولہویں صدی میں رامانندی اجودھیا میں آباد نہ تھے۔ اس زمانے میں شیو کی پوجا رام کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی۔ اٹھارہویں صدی سے رامانندی سادھو بڑے پیمانے پر آباد ہوئے۔ اس کے بعد ہی اجودھیا میں بہت سے مندر تعمیر کیے گئے۔ اب تک ایسا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ بابری مسجد اس اراضی پر بنائی گئی جہاں کہ کبھی کسی زمانے میں مندر تھا۔ مسجد کے دروازے پر فارسی کتبے یہ نہیں بتاتے کہ یہ مسجد بابر کی طرف سے بنوائی گئی۔
بابرنامہ کے پہلے انگریز مترجم بیورج یادداشت میں ایک ضمیمہ میں ان اشعار کا ترجمہ شائع کیا گیا ہے۔ بابرنامہ میں، جو کہ ان یادداشتوں کا مجموعہ ہے، لکھا ہے کہ شہنشاہ بابر کے حکم سے جس کا انصار اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے میرباقی نے فرشتوں کے اترنے کی ایک جگہ تعمیر کرائی۔ (بابرنامہ مترجم اے ایف بیوریج)۔ ان کتبوں میں صرف یہ دعوٰی کیا گیا تھا کہ بابر کے ایک امیر میرباقی نے مسجد تعمیر کرائی۔ یہ کہیں نہیں کہ یہ مسجد مندر کی جگہ پر تعمیر کرائی گئی۔ بابرنامہ میں بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں کہ یہاں اجودھیا میں اس مسجد کی تعمیر کے لیے کسی مندر کو توڑا گیا۔
آئینِ اکبری میں اجودھیا کا ذکر ہے۔ اسے رام چندر کی رہائش گاہ کہا گیا ہے جو کہ ترتیا میں روحانیت اور مادیت کا تھا لیکن اکبر کے دادا نے کسی بھی مندر کی جگہ مسجد تعمیر کرائی ہو اس کا ذکر نہیں ملتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تلسی داس جو کہ رام کا زبردست بھگت تھا اور جو اکبر کے عہد میں ہوا ہے اور جو اس خطے کا رہنے والا تھا ملیھ کے عروج پر پریشان ہے لیکن رام جنم بھومی کی جگہ مندر توڑے جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
انیسویں صدی میں اس کی کہانی سرکاری ریکارڈ میں داخل کی گئی اور دوسروں نے اسے تاریخی حوالہ سمجھ کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ مندر توڑنے کی کہانی بے بنیاد اور من گھڑت ہے اس کے لیے کوئی تاریخی ثبوت نہیں۔ ملاحظہ ہو ہسٹاریکل اسکیچ آف تحصیل فیض آباد لکھنؤ۔
ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان حکمران ہندوؤں کے مقدس مقامات کے دشمن رہے ہیں لیکن یہ بات تاریخ کی شہادتوں کی روشنی میں بے بنیاد نظر آتی ہے۔ مسلمان نوابوں کی سرپرستی میں اس کی توسیع ہوئی، نوابوں کی سرکار کالیئتھو کے تعاون سے چلتی تھی۔ مسلمان نوابوں کی افواج میں شیودھرم کے ماننے والا ناما تھے، ہندوؤں کے مقدس مقامات کے لیے تحائف اور جاگیریں دینے میں نواب پیش پیش رہے ہیں۔
(بشکریہ دیوبند ٹائمز)
کرنسی نوٹ، سودی قرضے اور اعضاء کی پیوندکاری
مختلف مکاتب فکر کے علماء کی ایک مشترکہ نشست
ادارہ
(بھارت کے دارالحکومت دہلی میں اسلامی فقہ اکیڈمی کی دعوت پر جدید مسائل کے سلسلہ میں منعقد ہونے والے علماء کے ایک سیمینار کی رپورٹ پندرہ روزہ ’’دیوبند ٹائمز‘‘ کے شکریہ کے ساتھ شائع کی جا رہی ہے۔ اے کاش کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے علماء کرام بھی فرقہ وارانہ مباحث سے بالاتر ہو کر قوم کو درپیش جدید مسائل کے حل کے لیے اجتماعی سوچ اور مشترکہ محنت کا راستہ اختیار کر سکیں ؎ ’’شاید کہ اتر جائے کسی دل میں مری بات‘‘)
اسلامی فقہ اکیڈمی کی دعوت پر دوسرا فقہی سیمینار ہمدرد یونیورسٹی کے کنونشن ہال میں ۸ سے ۱۱ دسمبر تک ہوا جس میں ہندوستان بھر سے ممتاز علماء اور فقہاء کے علاوہ جدید تعلیم یافتہ دانشوروں نے حصہ لیا۔ سیمینار کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں حنفی دیوبندی، بریلوی، شافعی، اور مسلک اہلِ حدیث سے تعلق رکھنے والے نمائندہ حضرات نے کھلی فضا میں زیربحث مسائل پر غور کیا اور اتفاق رائے سے فیصلے کیے۔
افتتاحی اجلاس میں کویت سے تشریف لانے والے ڈاکٹر جمال الدین عطیہ نے، جو فقہ کے ممتاز سکالر ہیں، اپنا کلیدی خطبہ پیش کیا اور پاکستان کے ممتاز عالم و مفتی مولانا محمد رفیع عثمانی نے کرسیٔ صدارت سے انتہائی بلیغ اور بصیرت افروز خطبہ دیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر منظور عالم (چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز نئی دہلی) نے خطبۂ استقبالیہ پیش کیا اور سیمینار کے داعی مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی (امین عام فقہ اکیڈمی) نے علماء اور فقہاء کے اس نمائندہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گذشتہ اپریل میں پہلا سیمینار اسی جگہ منعقد ہوا تھا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ہم یہاں پھر جمع ہوئے ہیں۔ جماعتی اور مسلکی حدبندیوں سے اوپر اٹھ کر ممتاز بالغ نظر فقہاء و اصحاب افتاء کا یہاں سر جوڑ کر بیٹھنا ایک فالِ نیک اور قابلِ ذکر امر ہے۔
سیمینار میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمٰن خیرآبادی، مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحی اور مفتی سعید احمد پالنپوری، جامعہ الارشاد اعظم گڑھ کے مولانا مجیب اللہ ندوی، ندوۃ العلماء کے مولانا عتیق احمد اور مولانا برہان الدین سنبھلی، بدایوں سے مفتی مطیع الرحمٰن رضوی، جامعہ سلفیہ بنارس کے ڈاکٹر مقتدی احسن ازہری، دارالعلوم ماٹلی والا گجرات کے مولانا ابوالحسن علی، اور علی گڑھ کے ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور مولانا مسعود عالم کی موجودگی نے مجلس کو اور نمائندہ و باوقار بنا دیا تھا۔ اس سیمینار میں ۷۰ کے قریب علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔
اجلاس میں نوٹ کی شرعی حیثیت، کرنسی پر افراطِ زر کے اثرات، اور سرکاری و غیر سرکاری سودی قرضوں سے پیدا ہونے والے فقہی مسائل پر مقالات پڑھے گئے۔ نیز گذشتہ سیمینار میں پگڑی اور اعضاء کی پیوندکاری کی جو بحث نامکمل رہ گئی تھی اس کی تکمیل کے بعد تجاویز کی منظوری دی گئی۔
اجلاس نے اس پر اتفاق کیا کہ سود قطعی حرام ہے، اور جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے، لیکن سود ادا کرنے کی حرمت بذاتِ خود نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سود خواری کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بعض خاص حالات میں عذر کی بنیاد پر سود ادا کر کے قرض لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کون عذر معتبر ہے، کون نہیں؟ نیز کون سی حاجت قابلِ لحاظ ہے اور کون سی نہیں؟ اس سلسلہ میں اصحابِ فتاوٰی کے مشوروں پر عمل کیا جائے۔ اجلاس نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ بعض سرکاری قرضوں میں حکومت کی طرف سے چھوٹ دی جاتی ہے اور سود کے نام سے زائد رقم بھی لی جاتی ہے۔ اگر یہ زائد رقم سبسڈی کے مساوی یا کم ہو تو یہ زائد رقم شرعاً سود نہیں ہے۔
اجلاس نے ہندوستانی مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کے مخصوص پس منظر میں سرکاری بینکوں سے ملنے والے ترقیاتی قرضوں اور ان پر وصول کیے جانے والے سود پر بھی غوروخوض کیا اور طے کیا کہ اسلامی فقہ اکیڈمی علماء اور ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دے جو مسئلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک رپورٹ پیش کرے تاکہ اگلے سیمینار میں غور کیا جا سکے۔
بحث کے دوران علماء کا عام رجحان تھا کہ ہندوستان اور اس جیسے دوسرے ملکوں کو دارالحرب قرار دے کر سود کے جواز کا فتوٰی نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں دارالحرب، دارالامن، اور دارالاسلام پر بحث ہوئی اور مقالات پیش ہوئے، ان کی روشنی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو اسلام کی دستوری ہدایات اور قانون بین الممالک کی روشنی میں اس بات پر غور کرے گی کہ آج کے دور میں موجودہ ملکوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ان کے کیا احکام ہوں گے اور ان میں بسنے والی مسلم آبادی کا کیا کردار حکومت اور دیگر عوام کے ساتھ ہونا چاہیئے۔
سیمینار میں غیر سودی بینکاری کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک جامع خاکہ کی ضرورت سے اتفاق کرتے ہوئے ایک ایسی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا جس میں علماء کے علاوہ معاشیات و بینکنگ کے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔
کرنسی نوٹوں پر بحث کے بعد اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ شریعت میں نوٹوں کی حیثیت زر اصطلاحی و قانونی کی ہے اس لیے ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سیمینار نے سفارش کی کہ مہر کا تعین سونے اور چاندی کی مقدار میں کیا جائے تو عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو گا اور کرنسی کی قوتِ خرید میں خسارہ سے ان پر اثر نہ پڑے گا۔
سیمینار نے اعضاء کی پیوندکاری اور خریدوفروخت پر بھی بحث کی اور تجاویز منظور کی گئیں۔ اس سیمینار نے نئے مسائل کے حل ڈھونڈنے میں علماء اسلام کی اجتہادی صلاحیت کا ثبوت پیش کیا ہے اور یہ کہ شریعت ہر زمانہ کے مسائل کا بہتر حل پیش کرتی ہے۔
آپ نے پوچھا
ادارہ
شرعی مہر ۳۲ روپے؟
سوال: عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ حق مہر شرعی طور پر ۳۲ روپے ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ (حافظ محمد سعید، کچا دروازہ، گوجرانوالہ)
جواب: اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، مہر کے بارے میں بہتر بات یہ ہے کہ خاوند کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیئے جسے وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ کچھ عرصہ قبل تک ایک سو بتیس روپے چھ آنے کو مہر فاطمی کے برابر سمجھا جاتا تھا جو کسی دور میں ممکن ہے صحیح ہو لیکن چاندی کی موجودہ قیمت کے لحاظ سے کسی صورت بھی یہ مہر فاطمی نہیں ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر پانچ سو درہم تھا، درہم چاندی کا سکہ تھا جس کا وزن ساڑھے تین ماشے بیان کیا جاتا ہے، اس حساب سے پانچ سو درہم کا وزن ساڑھے ستر سو ماشے بنتا ہے یعنی ایک سو پینتالیس تولے اور دس ماشے۔ اور ان دنوں (۱۹۹۰ء) چاندی کا بھاؤ کم و بیش ستر روپے تولہ ہے، اس طرح چاندی کی موجودہ قیمت کے حساب سے مہر فاطمی دس ہزار روپے سے زائد بنتا ہے۔
اس لیے بتیس روپے کو شرعی مہر قرار دینا درست نہیں ہے بلکہ احناف کے ہاں تو بتیس روپے مہر مقرر کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ احناف کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم متعین ہے جس کی بنیاد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہے کہ ’’لَا مَہْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَۃ دَرَاھِمْ‘‘ دس درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے۔ دس درہم کا وزن ایک ماشہ کم تین تولے ہے اور قیمت کے اعتبار سے دو سو روپے کے لگ بھگ رقم بنتی ہے۔ اس سلسلہ میں صاحبِ ہدایہؒ نے مہر کے باب میں احناف کے اس موقف کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی نے دس درہم سے کم مہر مقرر کر لیا تو بھی اسے کم از کم دس درہم (یعنی دو سو روپے کے لگ بھگ) ہی ادا کرنا ہوں گے۔
تیتو میر کون تھے؟
سوال: تحریکِ آزادی کے حوالہ سے بعض مضامین میں تیتومیرؒ کا ذکر آتا ہے، یہ کون بزرگ تھے اور تحریکِ آزادی میں ان کا کیا کردار ہے؟ (محمد عاصم بٹ، گکھڑ، ضلع گوجرانوالہ)
جواب: تیتومیرؒ کا نام نثار علی تھا، بنگال کے رہنے والے تھے، اپنے گاؤں نوکل باڑیہ میں لٹھ مار قسم کے نوجوان شمار ہوتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب امیر المؤمنین سید احمد شہیدؒ اور امام المجاہدین شاہ اسماعیل شہیدؒ جہادِ آزادی کی تیاری کے سلسلہ میں حجاز مقدس گئے ہوئے تھے۔ نثار علیؒ بھی اسی سال حج کے لیے گئے، سید احمد شہیدؒ سے ملاقات ہوئی، ان کی صحبت نے ذہن کا رخ بدل دیا۔ دل میں آزادی کا جذبہ انگڑائی لینے لگا، واپس آ کر علاقہ کے ہندو زمینداروں اور جاگیرداروں کے خلاف نوجوانوں کو منظم کرنا شروع کر دیا اور دینی اقدار کی ترویج کے لیے جدوجہد کی۔ نثار علیؒ کی محنت سے نوجوانوں کا ایک اچھا خاصا گروہ دینداری کی طرف مائل ہوا۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ڈاڑھی کی سنت بھی زندہ ہونے لگی۔ ہندو جاگیرداروں نے دینی بیداری کو خطرہ سمجھتے ہوئے اس رجحان کو قوت کے زور سے دبانا چاہا اور ڈاڑھی پر ٹیکس لگا دیا۔ نثار علیؒ کے گروہ نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، کشمکش بڑھی، محاذ آرائی کی صورت پیدا ہو گئی۔
نثار علیؒ نے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں مورچہ بندی کر لی اور اردگرد کے علاقہ پر علاقہ پر قبضہ کر کے انگریزی اقتدار کے خاتمہ اور مسلمانوں کی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں مجاہدین کے ساتھ نثار علیؒ نے یلغار شروع کی، انگریزی فوج اس کا سامنا نہ کر سکی اور بالآخر کلکتہ سے کمانڈر الیگزینڈر کی قیادت میں انگریزی لشکر مقابلہ کے لیے آیا اور اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد کلکتہ سے دوسرا انگریزی لشکر آیا اور اس سے مقابلہ کرتے ہوئے نثار علیؒ نے جو اب تیتو میر کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے جامِ شہادت نوش کیا اور ان کے متعدد ساتھیوں کو گرفتار کر کے بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ امیر المؤمنین سید احمد شہیدؒ نے بالاکوٹ میں مئی ۱۸۳۱ء میں جامِ شہادت نوش کیا جبکہ ان کے تربیت یافتہ بنگالی مجاہد نثار علی عرف تیتومیرؒ اسی سال نومبر یا دسمبر میں عروسِ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔
فئی اور غنیمت کا فرق؟
سوال: قرآن کریم میں غنیمت اور فئی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ (رشید احمد، دوبئی)
جواب: غنیمت اور فئے دونوں کفار سے حاصل شدہ مال کو کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ جو مال اور سامان میدانِ جنگ میں مقابلہ کے ساتھ کفار سے وصول ہو وہ غنیمت کہلاتا ہے، اور جو سازوسامان مسلمانوں کے لشکر سے مرعوب ہو کر لڑائی کے بغیر کفار چھوڑ کر چلے جائیں اسے فئے کہتے ہیں، یا جنگ کی صورت میں کفار کی جو زمین مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اسے بعد میں کفار ہی کے قبضہ میں چھوڑ کر ان پر جزیہ یا خراج عائد کر دیا جائے تو یہ آمدنی بھی فئی شمار ہوتی ہے۔
غنیمت اور فئے میں دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق غنیمت کا ایک خمس مال بیت المال کے لیے الگ کر کے باقی مال مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ فئی سارے کا سارا بیت المال کا حق ہے اور بیت المال کی تحویل میں جانے کے بعد بیت المال کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق اسے صرف کیا جا سکتا ہے۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’معالم العرفان فی دروس القرآن (سورہ المائدہ)‘‘
افادات: حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ
مرتب: الحاج لعل دین ایم اے۔
صفحات: ۵۱۶ قیمت مجلد ۱۲۵ روپے۔ کتابت و طباعت عمدہ
ملنے کے پتے: (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج، گوجرانوالہ (۲) ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ۔
حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ العالی کے دروس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے افادیت و قبولیت کے جس شرف سے نوازا ہے وہ حضرت صوفی صاحب مدظلہ کے خلوص، دینی معاملات میں ان کی متوازن سوچ، اظہارِ خیال میں اعتدال اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں پر ان کی گہری نظر کی علامت ہے۔ روزانہ نمازِ فجر کے بعد جامع مسجد نور میں دیے جانے والے ان دروس قرآن کو الحاج لعل دین صاحب بڑی محنت کے ساتھ مرتب کر رہے ہیں اور اب تک آخری دو پاروں کے علاوہ سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ النساء کے دروس سات ضخیم اور خوبصورت جلدوں کی صورت میں منظرِ عام پر آ چکے ہیں۔ اور زیر نظر آٹھویں جلد سورہ المائدہ کے ۵۴ دروس پر مشتمل ہے جس میں حضرت صوفی صاحب مدظلہ نے اپنے مخصوص انداز میں سورہ المائدہ کے معارف و مسائل کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ عام پڑھے لکھے لوگ ان سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں اور اہلِ علم بھی محظوظ ہوتے ہیں۔
سورہ المائدہ میں حلال و حرام کے مسائل کے علاوہ سرقہ، قتل اور ڈاکہ جیسے جرائم کے بارے میں شرعی احکام اور بنی اسرائیل کے مختلف احوال کا ذکر بطور خاص اہمیت کا حامل ہے اور حضرت صوفی صاحب مدظلہ نے ان امور کی وضاحت اس انداز سے کی ہے کہ مختلف حلقوں کی طرف سے ان امور کے بارے میں پھیلائے گئے شکوک و شبہات کا خودبخود ازالہ ہو جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت صوفی صاحب مدظلہ کو تادیر سلامت رکھیں اور ان کے افادات کو زیادہ سے زیادہ خلقِ خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، آمین یا الٰہ العالمین۔
’’انگریز کے باغی مسلمان‘‘
مصنف: جانباز مرزا
صفحات ۴۸۸ قیمت مجلد ۷۵ روپے۔ سرورق خوبصورت، کتابت و طباعت معیاری
ملنے کا پتہ: مکتبہ تبصرہ ۷/۴ گلشن کالونی، بادامی باغ، لاہور
جانباز مرزا باہمت بزرگ ہیں جو عمر کے اس حصہ میں ماضی، حال اور مستقبل سے بے خبر نئی نسل کو اس کے پرجوش ماضی کی یاد دلانے پر کمربستہ ہیں اور اپنے بڑھاپے اور بے سروسامانی کی پروا کیے بغیر اشاعتی محاذ پر ایک ادارے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جانباز مرزا نے آٹھ جلدوں میں ’’کاروانِ احرار‘‘ لکھی، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی زندگی اور جدوجہد کو ایک مستقل کتاب ’’حیاتِ امیر شریعت‘‘ میں سمویا، جیل کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے انسانیت پر ہونے والے مظالم کا نقشہ ’’بڑھتا ہے ذوق جرم‘‘ میں پورے درد دل کے ساتھ کھینچا، تحریک ختم نبوت کی مرحلہ وار کہانی مرتب کی، اور اب ’’انگریز کے باغی مسلمان‘‘ کے عنوان سے ان مردانِ حر کے احوال و واقعات کو حیطۂ تحریر میں لا رہے ہیں جنہوں نے برٹش استعمار کے دورِ عروج میں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے سامراج کو للکارا اور بالآخر مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد اسے برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش سے بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔
’’انگریز کے باغی مسلمان‘‘ کی پہلی جلد اس وقت ہمارے سامنے ہے جس کے سرورق پر مولانا عبید اللہ سندھیؒ، خان عبد الغفار خانؒ، مولانا حسرت موہانیؒ، مولانا احمد علی لاہوریؒ، مولانا ابوالکلام آزادؒ اور امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے تصویری خاکے ہیں۔ اور اندرونی صفحات ۱۷۵۷ء سے ۱۸۹۴ء تک کی داستان حریت پر مشتمل ہیں اور ان میں داستانِ حریت کے مرکزی کرداروں نواب سراج الدولہؒ، نواب حیدر علیؒ، ٹیپو سلطانؒ، شاہ عبد العزیزؒ، حافظ رحمت خانؒ، بہادر شاہ ظفرؒ، سید احمد شہیدؒ، شاہ اسماعیل شہیدؒ، تیتو میر شہیدؒ، رائے احمد خان کھرل شہیدؒ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ، اور سید جمال الدین افغانیؒ جیسے عظیم مجاہدین آزادی کے معرکہ ہائے حریت و استقلال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
’’اپنی ذات میں ایک انجمن‘‘ کا محاورہ عام طور پر بڑی شخصیات کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے کے لوگوں میں اگر یہ محاورہ کسی شخصیت پر فٹ آتا ہے تو وہ جانباز مرزا ہیں جو اپنی زندگی کے آٹھویں عشرہ کو بھی شاید عبور کر چکے ہیں لیکن لائبریریوں میں گھوم کر خود مواد اکٹھا کرتے ہیں، اسے ترتیب دیتے ہیں، اپنے بڑے اور لائق و فرمانبردار فرزند جناب خالد مرزا کو املاء کراتے ہیں، اپنی نگرانی میں خود کتابت کراتے ہیں، پروف ریڈنگ کرتے ہیں، چھپواتے ہیں، بستی بستی خود پہنچ کر کتاب اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور کتاب کے تعارفی پوسٹر اپنے ہاتھوں سے دیواروں پر چسپاں کرتے ہیں۔ آج ہی صبح وہ ’’الشریعہ‘‘ کے دفتر میں اپنی کتاب دینے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی، انہوں نے گٹھڑی کھولی، اس میں سے ایک پوسٹر نکالا، ایک پوٹلی کھولی جس میں لئی تھی، پوسٹر پر خود لئی لگائی اور جامع مسجد کے مین گیٹ پر اسے اپنے ہاتھوں سے چسپاں کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر جانباز مرزا کی عزت نفس کے احترام نے انہیں پلکوں کی سرحد عبور نہ کرنے دی۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردِ درویش کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے اشاعتی منصوبے مکمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائیں کہ آج کے دور میں جبکہ وسائل و اسباب سے مالامال اشاعتی ادارے تاریخ کا چہرہ مسخ کرنے اور ماضی کی حقیقتوں پر مصلحتوں کے پردے ڈالنے پر تلے بیٹھے ہیں، جانباز مرزا جیسے ٹمٹماتے چراغ بھی اگر بجھ گئے تو ماضی کے حقائق کے ساتھ ہمارا رشتہ آخر کون قائم رکھے گا؟
’’آئینہ قادیانیت‘‘
مصنف: مولانا محمد فیروز خان
صفحات: ۱۴۴
ملنے کا پتہ: دارالعلوم مدنیہ، ڈسکہ، ضلع سیالکوٹ
قادیانیت ہمارے معاشرے کا ایک رستا ہوا ناسور ہے جس کے جراثیم فرنگی استعمار نے اپنے مخصوص نوآبادیاتی مقاصد کے لیے ملتِ اسلامیہ کے جسم میں داخل کیے اور پھر ان کی ایسے سرپرستی اور پرورش کی کہ اس کی جڑیں عالمِ اسلام کے مختلف حصوں تک پھیل گئیں۔ قادیانیت کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی مفردات و نقصانات پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور علماء امت نے اس فتنہ کے ہر پہلو کو بے نقاب کیا ہے۔ زیرنظر رسالہ میں ہمارے محترم بزرگ مولانا محمد فیروز خان فاضل دیوبند نے قادیانیت کے بارے میں اپنی یادداشتوں کو مرتب کیا ہے۔ معلوماتی رسالہ ہے اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس کا مطالعہ بے حد مفید ہو گا۔
’’عورت کی سربراہی کا مسئلہ اور شبہات و مغالطات کا ایک جائزہ‘‘
تالیف: حافظ صلاح الدین یوسف
صفحات: ۱۳۰
ملنے کا پتہ: دارالدعوہ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور
عورت کی حکمرانی کا مسئلہ قرآن و سنت اور اجماع امت کی رو سے طے شدہ امر ہے اور اس بات پر امت کے تمام مکاتبِ فکر کا چودہ سو سال سے اجماع چلا آتا ہے کہ کسی مسلم ریاست میں عورت کو حکمرانی کے منصب پر فائز کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ مگر یورپی سیاست کی پیروی کا شوق بعض حضرات پر اس درجہ غالب آگیا ہے کہ وہ اس اجماعی اور مسلّمہ مسئلہ کو بھی شکوک و شبہات اور مغالطات پیدا کر کے متنازعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور بالکل اسی انداز سے دلائل کشید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ختم نبوت جیسے اجماعی عقیدہ کے خلاف قادیانی علماء قرآن و سنت سے خودساختہ دلائل کشید کر کے امت کو دھوکہ دینے کے درپے رہے ہیں۔
ہفت روزہ الاعتصام لاہور کے فاضل مدیر مولانا حافظ صلاح الدین یوسف نے زیرنظر کتابچہ میں انہی لوگوں کے خودساختہ دلائل کا جائزہ لیا ہے اور مغرب زدہ عناصر کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کے تاروپود بکھیر کر اس حقیقت کا ایک بار پھر اثبات کیا ہے کہ اسلام کے مسلّمہ اصول اور دلائل کی روشنی میں عورت کی حکمرانی کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
تختۂ کابل الٹنا چند دن کی بات ہے
سرور میواتی
عزم و ہمت کے دھنی، آنِ وطن کے پاسباں
اے مجاہد عظمتِ اسلام کے تاباں نشاں
تیری عظمت کےمقابل سرنگوں ہے آسماں
تو نے استبداد کے ایواں ہلا کر رکھ دیے
روس کے ارمان مٹی میں ملا کر رکھ دیے
پھول فتح و کامرانی کے کھلا کر رکھ دیے
مرحبا صد مرحبا افغاں مجاہد شاد باد
ہے ترا مقصد خدا کی راہ میں کرنا جہاد
کاٹ دے پائے جہاں بیخ و بن شر و فساد
کر دیے مسمار تو نے آمریت کے حصار
بربریت کے نظر آتے ہیں اب ہر سو مزار
ہے ہمیشہ سے یہی اللہ والوں کا شعار
سطوتِ اسلام کے تو نے عَلم لہرا دیے
روس کے نمرود کو ناکوں چنے چبوا دیے
سرد سینوں میں الاؤ جوش کے دہکا دیے
ناک میں دم کر کے چھوڑا تو نے میخائیل کا
توڑ پھینکا زعمِ باطل ہندو اسرائیل کا
پھر گیا نقشہ نگاہوں میں صاحبِ فیل کا
فلیقاتل فی سبیل اللہ ہے مقصد ترا
چشمِ یزداں میں عمل مقبول ہے بے حد ترا
ہو گیا ہے محفلِ عالم میں اونچا قد ترا
راہِ دیں میں جہدِ پیہم جب تری دن رات ہے
فتح و تائیدِ خداوندی بھی تیرے ساتھ ہے
تختۂ کابل الٹنا چند دن کی بات ہے
روزے کا فلسفہ
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
عبادت کا ایک طریقہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کے لیے شدید و ثقیل مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے سخت دل بستگی اور قلبی محبت کرتا ہے تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی اپنی زندگی اور مرافقِ حیات درست ہیں یا نہیں اور وہ عیش و آرام میں ہے یا تکلیف و رنج میں۔
محبوبِ حقیقی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اقوامِ عالم نے مختلف مسلک اختیار کیے ہیں، بعض لوگوں نے سخت سے سخت جسمانی تکلیف اٹھانا موجبِ سعادت اور باعثِ رضائے الٰہی سمجھا اور ایسے متاعبِ شاقہ کو ضروری سمجھا ہے جن میں فطرتِ انسانی اور خلق اللہ کی تبدیلی نظر آتی ہے۔ مثلاً وہ کسی عضو شریف کو مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ کو ایک ہی حالت میں رکھ کر اس کو خشک کر لیتے ہیں، یا عمر بھر تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ عضوِ تناسل کاٹ لیتے ہیں اور قوتِ مردمی کا کلی استیصال کرتے ہیں، یا اس قسم کی اور بے شمار دوسری باتیں جو سنتِ الٰہی کے خلاف ہیں۔
یہ یاد رکھو کہ یہ سب طریقے جاہلانہ طریقے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے والے عابدوں کو معبودِ حقیقی کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان سے خلق اللہ اور سنتِ الٰہی کی تغیر و تبدیلی آتی ہے۔ اس کی سب سے اچھی اور بہترین صورت وہی ہے جس میں بڑی بڑی نفسانی خواہشات و لذات مثلاً کھانا پینا اور جنسی تعلق کو اتنی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جو نہ تو بہت کم ہو جس کا کچھ اثر ظاہر و محسوس نہ ہو، اور نہ اتنی دیر تک خواہشات مذکورہ کو ترک کیا جائے کہ ریاضت کرنے والے کے جسم اور اس کے قوائے بدنیہ پر مضر اثر پڑے اور فساد مزاج کا باعث ہو۔
(البدور البازغہ مترجم ۔ ص ۳۰۶)
سرمایہ داری کا بت
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
ہندو جب بھی کوئی نیا نظام پیدا کرتا ہے تو اس کی بنیاد سرمایہ داری پر ہوتی ہے۔ چنانچہ گاندھی جی جیسا شخص بھی انسانیت کا اتنا بڑا نمائندہ بن کر سرمایہ داری سے ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو کمیونسٹ ہیں مگر وہ بھی سرمایہ دار ہیں۔ ان کے مقابلہ میں حسرت موہانی کو لیجئے، جس دن اس نے اشتراکیت قبول کی وہ اپنی تمام جائیداد ختم کر چکا اور اب وہ ایک کوڑی کا بھی مالک نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے یورپ جا کر سوشلسٹوں کے ساتھ رہ کر سوشلزم سیکھا مگر حسرت اپنی ذاتی کاوش سے اس مرتبہ پر پہنچے۔ یہ فرق ہے مسلم سوسائٹی اور ہندو سوسائٹی میں، مسلم جس وقت اپنے اصلی نظام پر آئے گا وہ سرمایہ داری کا بت توڑنے والا ہو گا اور آج دنیا میں سرمایہ داری کے سوا کونسا بڑا بت ہے جسے توڑنے کی ضرورت ہے؟
(خطبات و مقالات ۔ ص ۸۸)
مشاورت کا مسئلہ اسلام میں بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اسلامی حکومتوں کو شورٰی سے خالی کر کے مطلق العنان جاہل حکمرانوں اور امیروں کا کھیل بنا دیا گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی امانت (سرکاری خزانے) سے اپنی شہوت پرستیوں پر خرچ کرتے ہیں اور وہ بڑی بڑی مصلحتوں کے مقابلہ میں خیانت کرتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس قسم کی غلطیوں کا خمیازہ مسلمانوں کو اس غلط تفسیر کی وجہ سے بھگتنا پڑا۔ ورنہ ہر ایک مسلمان ایک حاکم کے اوپر ننگی تلوار ہے، وہ حاکم کیوں قانونِ الٰہی کی اطاعت نہیں کرتا؟ اگر وہ اطاعت نہیں کرتا تو کس بنا پر ہم سے اطاعت کا طلبگار ہوتا ہے؟ یہ طاقت مسلمانوں میں پھر سے پیدا ہو سکتی ہے اور اس سے ان کی جماعتی زندگی آسانی کے ساتھ قرآن کے مطابق بن سکتی ہے۔
(عنوانِ انقلاب ۔ ص ۱۲۶)
مئی ۱۹۹۰ء
مسلم سربراہ کانفرنس ۔ وقت کا اہم تقاضہ
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
گزشتہ ہفتے سعودی مملکت کے فرمانروا شاہ فہد کے ساتھ حکومت پاکستان کے ایک وفد کی ملاقات کے حوالے سے یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی ہے کہ شاہ فہد مسئلہ کشمیر پر اسلامی سربراہ کانفرنس بلانے والے ہیں۔ معلوم نہیں اس خبر کی حقیقت کیا ہے لیکن جہاں تک اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس طلب کرنے کی ضرورت ہے اس سے انکار یا صرفِ نظر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔
کشمیری حریت پسند جس جرأت و استقلال کے ساتھ حصولِ آزادی کے لیے اپنے خون کی قربانی دے رہے ہیں اور افغان مجاہدین کے گیارہ سالہ کامیاب جہادِ آزادی کو آخری مراحل میں جس طرح سازشوں کے ذریعے ناکامی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا تقاضا ہے کہ مسلم سربراہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور افغانستان و کشمیر کے ساتھ ساتھ فلسطین، آذربائیجان، مورو، ایریٹیریا، اراکان (برما) اور وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں میں ابھرنے والی آزادی کی تحریکات کے حوالہ سے اپنے اجتماعی کردار کا تعین کریں۔
یہ درست ہے کہ مسلم ممالک کے بیشتر موجودہ حکمرانوں کے شخصی اور گروہی مفادات استعماری قوتوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ اس وقت اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ عالم اسلام میں آزادی، غلبۂ اسلام اور دینی بیداری کے بڑھتے ہوئے رجحانات کا ساتھ دیں یا مسلم ممالک کے موجودہ فرسودہ انتظامی، سیاسی اور اقتصادی ڈھانچوں کے تحفظ کی ناکام تگ و دو میں لگے رہیں۔ لیکن مسلم حکمرانوں کو ایک بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ عالم اسلام اب خواب غفلت سے بیدار ہو رہا ہے اور اگر ان حکمرانوں نے بیداری اور آزادی کی ان لہروں کے مخالف سمت چلنے کی کوشش کی تو تاریخ میں ان کا یہ جرم کبھی معاف نہیں ہوگا۔
اس پس منظر میں اسلامی سربراہ کانفرنس کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلم حکمران اگر اپنے مثبت اور مؤثر کردار کا تعین کرتے ہیں تو نہ صرف افغانستان، کشمیر، فلسطین اور دیگر خطوں کے مظلوم مسلمان ان کے شکر گزار ہوں گے بلکہ انہیں اپنی گزشتہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کا راستہ بھی مل جائے گا۔
مسلم اجتماعیت کے ناگزیر تقاضے
مولانا ابوالکلام آزاد
جناب ابو سلمان شاہجہانپوری کی تصنیف ’’تحریک نظم جماعت‘‘ سے ایک انتخاب۔
ترتیب و انتخاب: مولانا سراج نعمانی، نوشہرہ صدر
۱۹۱۶ء کے لیل و نہار قریب الاختتام تھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت اس عاجز پر منکشف کی اور مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک یہ عقدہ حل نہ ہو گا ہماری کوئی سعی و جستجو کامیاب نہ ہو گی۔ چنانچہ اسی وقت سے سرگرم سعی و تدبیر ہو گیا (ص ۳۱)۔
۱۹۱۶ء کی بات ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ ہندوستان کے علماء و مشائخ کو عزائم و مقاصدِ وقت پر توجہ دلاؤں، ممکن ہے چند اصحابِ رشد و عمل نکل آئیں۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش کی لیکن ایک شخصیت کو مستثنٰی کر دینے کے بعد سب کا متفقہ جواب یہی تھا کہ یہ دعوت ایک فتنہ ہے ’’اِئْذَنْ لِّیْ وَلَا تَفْتِنِّیْ‘‘۔ یہ مستثنٰی شخصیت مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ کی تھی جو اَب رحمتِ الٰہی کے جوار میں پہنچ چکی ہے (ص ۵۴)۔
۱۹۱۴ء میں جب میں نے ہندوستان کے بعض اکابر علماء و مشائخ کو عزم و سعی کی دعوت دی، بعض سے خود ملا اور بعض کے پاس مولوی عبید اللہ سندھیؒ کو بھیجا تو اکثر نے بعینہٖ یہی بات کی تھی جو آپ (مولانا محی الدین قصوری) کہہ رہے ہیں کہ علماء و مشائخ کی اتنی بڑی تعداد ملک میں موجود ہے کسی نے بھی آج تک یہ دعوت نہیں دی، اب سواد اعظم کے خلاف یہ قدم کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ (ص ۵۴)
پروگرام
۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۸ء تک کے حوادثِ عالم کا سیلاب اگرچہ نہایت مہیب اور بہت مشکل تھا کہ ارادے اور فیصلے کی دیواریں اس کے مقابلے میں قائم رہ سکیں، عنایت الٰہی کی دستگیری سے میں نے اپنے ارادے اور عزم کو اس وقت بھی پوری طرح قائم و استوار پایا اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل پر مایوسی کو قبضہ نہ ملا۔ واقعات کی خطرناکی اور ناکامی میرے دل و جگر کو چیرا دے سکتی تھی اور حوادث کی غم گینی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی تھی لیکن وہ اس یقین و عزم کو نہیں نکال سکتی تھی جو اس کے ریشے ریشے میں بسا ہوا ہے اور صرف اسی وقت نکل سکتا ہے جب دل بھی سینے سے نکل جائے۔ وہ زمین کی پیداوار نہیں کہ زمین کی کوئی طاقت اسے پامال کر سکے، وہ آسمان کی روح ہے ’’تَتَنَزَّلُ عَلَیْھِمُ الْمَلَائِکَۃُ اَن لَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا‘‘ آسمان کی بلندیوں سے اتری ہے۔ پس نہ تو زمین کی امیدیں اسے پیدا کر سکتی ہیں اور نہ زمین کی مایوسیاں اسے ہلاک کر سکتی ہیں۔
۱۹۱۸ء کے اواخر میں میں رانچی کے ایک گوشۂ عزلت میں بیٹھا ہوا ایک نئی امید کی تعمیر کا سروسامان دیکھ رہا تھا اور گویا دنیا نے ایک دروازے کے بند ہونے کی صدائیں سنی تھیں مگر میرے کان ایک نئے دروازے کے کھلنے پر لگے ہوئے تھے ؎
تفاوت است میان شنیدن من و تو
تو بستن در، و من فتح باب می شنوم
۱۹۱۸ء کے رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ اور اس کی بیدار و معمور راتیں تھیں کہ جب میں نے ان ہی ہاتھوں سے امیدوں اور آرزوؤں کے نئے نقشوں پر لکیریں کھینچیں (ص ۶۰)۔
یکم جنوری ۱۹۲۰ء کو جب مجھے چار سال کی نظربندی سے رہا کیا گیا تو میں اپنی آئندہ زندگی، زندگی کے کاموں اور طریق و اسلوب کی نسبت خالی الذہن نہ تھا اور نہ اپنے ارادے کے بہنے کے لیے کسی سیلاب کا منتظر تھا۔ میں نے ہمیشہ بہنے کی جگہ چلنے کی کوشش کی ہے ۔۔۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیئے اور میری مشغولیت کا عنوان و طریق کیا ہو گا (ص ۵۷)۔
نقشۂ کار
(۱) رفقاء و طالبین کی ایک جماعت کی تعلیم و تربیت
(۲) تصنیف و تالیف
(۳) جماعتی اعمال یعنی تنظیم جماعت
چنانچہ جنوری ۱۹۲۰ء میں جب میں نظربندی کے گوشۂ قید و بند سے نکلا تو دو سال پیشتر کا یہ نقشۂ عمل میرے سامنے تھا اور اس لیے نہ تو مجھے واقعات کی رفتار کا انتظار تھا نہ مزید غوروفکر کا، بلکہ صرف شغل عمل ہی شروع کر دینا تھا۔ میں نے آئندہ کے لیے جن امور کا ارادہ کیا تھا ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رانچی سے نکلتے ہی کسی عزلت میں رفقاء و طالبین کی ایک جماعت لے کر بیٹھ رہوں گا اور اپنی زبان و قلم کی خدمات میں مشغول ہو جاؤں گا۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ جو جماعتی اعمال پیشِ نظر تھے ان کے لیے بھی سیر و گردش اور نقل و حرکت کی ضرورت نہ تھی، قیام و استقرار ہی مطلوب تھا۔ چنانچہ اس بناء پر رہائی کے بعد سیدھا کلکتہ کا قصد کیا۔ اگرچہ تمام ملک سے پیغام ہائے طلب و دعوت آ رہے تھے اور ہر طرف نظربندوں کی رہائی پر ہنگامہ تہنیت و تبریک گرم تھا لیکن میں کہیں نہ جا سکا اور سب سے عذر خواہ ہوا (ص ۶۱)۔
مولانا آزاد کی دعوتِ اتحاد و تنظیم پر طبقاتی ردِعمل
جدید تعلیم یافتہ طبقے کا ردعمل
مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے جمعیۃ علماء ہند کے اجلاس کلکتہ میں یہ خدشہ ظاہر فرمایا تھا کہ
’’تعلیم یافتہ حضرات کو شبہ ہے کہ علماء اس پردے میں اپنی کھوئی ہوئی وجاہت کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔‘‘
ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:
’’۱۹۸۰ء میں معارف میں اس تحریک کو اٹھایا گیا اور اصلاحات کے سلسلہ میں اس کو پیش کیا گیا۔ پھر ۱۹۲۰ء میں یورپ سے واپسی کے بعد چاہا کہ اس کو تمام ہندوستان کا مسئلہ بنا دیا جائے مگر اس عہد کی جدید تعلیم کے علمبرداروں نے اس کو کسی طرح نہ چلنے دیا۔‘‘ (ص ۱۰۳)
پیروں کا کردار
مولانا آزاد کے خلیفہ اور سندھ میں اجتماعیت کے داعی شاہ سائیں مرحوم نے سندھ کی حد تک سندھ پیروں اور مشائخ کو متحد اور متفق کرنے کے لیے اَن تھک کوشش کی جسے علی محمد راشدی کے الفاظ میں پڑھیئے:
’’شاہ سائیں کا خیال تھا کہ ان سادہ لوحوں (پیروں) کو انگریز مداری کے بندر کی طرح نچائے گا۔ انہیں عوامی مصلحت اور مقاصد کے خلاف استعمال کرے گا۔ پھر جب یہ سوا اور بدنام ہو جائیں گے تو ہاتھ کھینچ لے گا۔۔۔ وہ چاہتے تھے کہ پیروں کو سرکار اور عام لیڈروں کے چکروں سے نکال کر عوام کے قریب رکھا جائے اور آزادی کی جدوجہد اور عوامی زندگی میں ان سے کام لیا جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیر سرکاری دلّال بن کر عوام سے دور، سیاسی بصیرت سے بے بہرہ، خدمت قومی سے معطل، اور مریدوں کی صرف نذر کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں ۔۔۔ اپنی تحریک کی ناکامی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اس فرقے کو تو بھیک کی عادت پڑ گئی ہے اور سچے پیر انتقال کر گئے۔ ان کی جگہ گداگر بیٹھتے جا رہے ہیں۔ گداگروں کا کیا اخلاق ہوتا ہے، کسی دن بڑوں کی قبریں بھی بیچ دیں گے۔‘‘ (ص ۱۷۱)
علماء سو کا اعتراف
مولانا آزاد مرحوم اپنی تحریک کی ناکامی کا ذمہ دار علماء سو کے جمود اور وقت کی عدم مساعدت کو قرار دیتے ہیں۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:
میں اپنے پندرہ سال کے طلب و عشق کے بعد وقت کی عدم مساعدت و استعداد کا اعتراف کرتا ہوں ۔۔۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ طبقہ علماء سے میں قطعاً مایوس ہوں اور اس کو قوانین اجتماع کے بالکل خلاف سمجھتا ہوں کہ ان کے جمود میں کسی طرح کا تقلب و تحول پیدا ہو۔ (ص ۱۰۱)
مولانا آزاد مرحوم کی نظر میں قائد و امام کی خصوصیات
ایک صاحبِ نظر و اجتہاد دماغ کی ضرورت ہے جس کا قلب کتاب و سنت کے غوامض سے معمور ہو۔ وہ اصولِ شرعیہ کو مسلمانانِ ہند کی موجودہ حالت پر ان کے توطنِ ہند کی حدیث العہد نوعیت پر، ایک ایک لمحے کے اندر متغیر ہو جانے والے حوادثِ جنگ و صلح پر ٹھیک ٹھیک منطبق کر لے، اور پھر تمام مصالح و مقاصدِ شرعیہ و ملیہ کے تحفظ و توازن کے بعد فتوٰی جاری کرتا رہے۔ آج ایک ایسے عازم امر کی ضرورت ہے جو وقت اور وقت کے سروسامان کو نہ دیکھے بلکہ وقت اپنے سارے سامانوں سمیت اس کی راہ تک رہا ہو۔ مشکلیں اس کی راہ میں گردوغبار و خاکستر بن کر اڑ جائیں اور دشواریاں اس کے جولانِ قدم کے نیچے خس و خاشاک بن کر پس جائیں۔ وہ وقت کا مخلوق نہ ہو کہ وقت کے حاکموں کی چاکری کرے، وہ وقت کا خالق و مالک ہو اور زمانہ اس کی جنبشِ لب پر حرکت کرے۔ اگر انسان اس کی طرف سے منہ موڑ لیں تو وہ خدا کے فرشتوں کو بلا لے۔ اگر دنیا اس کا ساتھ نہ دے تو وہ آسمان کو اپنی رفاقت کے لیے نیچے اتار لے۔ اس کا علم مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہو۔ اس کا قدم منہاجِ نبوت پر استوار ہو۔ اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ حکمتِ رسالت کے تمام اسرار و غوامض اور معالجہ اقوام و طبابت، عہد و ایام کے تمام سرائر و خفایا اس طرح کھول دے کہ وہ صرف ایک صحیفہ کتاب و سنت اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا کی ساری مشکلوں کے مقابلے اور ارواح و قلوب کی ساری بیماریوں کی شفاء کا اعلان کر دے ’’وَمَا ذٰلِکَ عَلَی اللہِ بِعَزِیْز‘‘ (ص ۳۴)۔
موجودہ وقت کسی ایسے مردِ راہ کا طالب ہے جو صاحبِ عزم و امر ہو اور اس لیے نہ ہو کہ دوسروں کی چوکھٹ پر ہدایت و راہنمائی کے لیے سر جھکائے بلکہ دوسرے اس لیے ہوں تاکہ راہنمائی کے لیے اس کا منہ تکیں اور جب وہ قدم اٹھائے تو اس کے نقشِ قدم کو دلیلِ راہ بنائیں ۔۔۔ وہ اپنے اندر مصباح ہدایت کی روشنی رکھتا ہو جو باہر کی تمام روشنیوں سے بے پروا کر دے (ص ۲۹۷)۔ یہ کام صرف ایک صاحبِ نظر و اجتہاد کا ہے جس کو قوم نے بالاتفاق تسلیم کر لیا ہو۔ وہ وقت اور حالت پر اصولِ شریعت کو منطبق کرے گا۔ ایک ایک جزئیہ حوادث و واقعات پر پوری کاروانی اور نکتہ شناسی کے ساتھ نظر ڈالے گا۔ امت و شرع کے اصولی مصالح و فوائد اس کے سامنے ہوں گے۔ کسی ایک گوشے ہی میں ایسا مستغرق نہ ہو جائے کہ باقی تمام گوشوں سے بے پروا ہو جائے۔
؏ حَفِظْتَ شَیْئًا وَ غَابَتْ عَنْکَ اَشْیَآء
سب سے بڑھ کر یہ کہ اعمال مہمہ امت کی راہ میں منہاجِ نبوت پر اس کا قدم استوار ہو گا اور ان ساری باتوں کے بعد علم و بصیرت کے ساتھ ہر وقت، ہر تغیر، ہر حالت کے لیے احکامِ شرعیہ کا استنباط کرے گا (ص ۳۶)
کاش مجھ میں ایسی قوت ہوتی یا وہ شے موجود ہوتی جس کی مدد سے میں تمہارے مقفل قلوب کے پٹ کھول سکتا تاکہ میری آواز تمہارے کانوں میں نہیں بلکہ تمہارے دل میں سما سکتی اور تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتے (ص ۹۵)۔
جماعتی زندگی کی خصوصیات
کتاب و سنت نے جماعتی زندگی کے تین رکن بتائے ہیں:
(ا) تمام لوگ کسی صاحبِ علم و عمل پر جمع ہو جائیں اور وہ ان کا امام ہو۔
(ب) جو کچھ وہ تعلیم دے ایمان و صداقت کے ساتھ قبول کریں۔
(ج) قرآن و سنت کے ماتحت اس کے جو احکام ہوں ان کی بلا چون و چرا تعمیل و اطاعت کریں۔ سب کی زبانیں گونگی ہوں، صرف اسی کی زبان گویا ہو۔ سب کے دماغ بیکار ہو جائیں، صرف اسی کا دماغ کارفرما ہو۔ لوگوں کے پاس نہ زبان ہو نہ دماغ، صرف دل ہو جو قبول کرے، صرف ہاتھ پاؤں ہوں جو عمل کریں (ص ۳۰)۔
اجتماعیت کے قیام کے لیے شیخ الہند سے رابطہ
شیخ الہندؒ سے ملاقات
مولانا ابوالکلام فرماتے ہیں: حضرت مولانا محمود الحسنؒ سے میری ملاقات بھی دراصل اسی طلب و سعی کا نتیجہ تھی، انہوں نے پہلی ہی صحبت میں کامل اتفاق ظاہر فرمایا تھا اور یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا تھا کہ وہ اس منصب کو قبول کر لیں گے اور ہندوستان میں نظم جماعت کے قیام کا اندازہ کر لیا جائے گا۔ مگر افسوس ہے کہ بعض زود رائے اشخاص کے مشورے سے مولانا نے اچانک سفرِ حجاز کا ارادہ کر لیا اور میری کوئی منت سماجت بھی انہیں سفر سے باز نہ رکھ سکی (ص ۳۲)۔
شیخ الہندؒ کی تائید
مولانا عبد الرزاق ملیح آبادیؒ فرماتے ہیں:
’’میں نے شیخ الہندؒ سے (فرنگی محل لکھنؤ میں) تنہائی میں ملاقات کی۔ رسمی باتوں کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی امامت کا تذکرہ چھیڑا۔ شیخ الہندؒ نے فرمایا، امامت کی ضرورت مسلّم ہے۔ عرض کیا، حضور سے زیادہ کون اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس منصب کے لیے وہی شخص موزوں ہو سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ہوش مند، مدبر اور ڈپلومیٹ ہو، جس کی استقامت کو نہ تو کوئی تشویش متزلزل کر سکے نہ کوئی ترہیب۔۔۔ شیخ الہندؒ نے اتفاق ظاہر کیا تو عرض کیا کہ آپ کی رائے میں اس وقت امامت کا اہل کون ہے؟ یہ بھی اشارۃً کہہ دیا کہ بعض لوگ اس منصب کے لیے خود آپ کا نام لے رہے ہیں اور بحمد اللہ اہل بھی ہیں۔ شیخ بڑی معصومیت سے مسکرائے اور فرمایا، میں ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کا امام بنوں۔ عرض کیا کہ کچھ لوگ مولانا عبد الباری صاحب (فرنگی محلی) کا نام لے رہے ہیں۔ موصوف کا تقوٰی و استقامت مسلّم ہے مگر مزاج کی کیفیت سے آپ بھی واقف ہیں۔ شیخ نے سادگی سے جواب دیا، مولانا عبد الباری کے بہترین آدمی ہونے میں شبہ نہیں مگر منصب کی ذمہ داریاں کچھ اور ہی ہیں۔ عرض کیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ نے متانت سے فرمایا، میرا انتخاب بھی یہی ہے، اس وقت مولانا آزاد کے سوا کوئی شخص ’’امام الہند‘‘ نہیں ہو سکتا‘‘۔
مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں:
’’ایک دفعہ جیسا کہ میں نے سنا ہے لاہور میں دیوبند کی جماعت کے سربرآوردہ حضرات نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیعت کے ساتھ رضامندی کا اعلان کر دیا تھا۔ خیال آتا ہے کہ مولانا انور شاہ (کاشمیری)، مولانا شبیر احمد (عثمانی) اور مولانا حبیب الرحمٰن (دیوبندی) جیسی ممتاز ہستیوں کی طرف سے اس رضامندی کا اعلان کیا جا چکا تھا مگر اعلان سے آگے بات نہ بڑھی۔‘‘ (ص ۸۵)
شیخ الہند
مولانا مرحوم ہندوستان کے گذشتہ دور کے علماء کی آخری یادگار تھے، ان کی زندگی اس دور حرمان و فقدان میں علماء حق کے اوصاف و خصائل کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کا آخری زمانہ جن اعمالِ حقہ میں بسر ہوا وہ علماء ہند کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ ستر برس کی عمر میں، جب ان کا قد ان کے دل کی طرح اللہ کے آگے جھک چکا تھا، عین جوارِ رحمت میں گرفتار کیا گیا اور کامل تین سال تک جزیرہ مالٹا میں نظربند رہے۔ یہ مصیبت انہیں صرف اس لیے برداشت کرنی پڑی کہ اسلام اور ملتِ اسلام کی تباہی و بربادی پر ان کا خدا پرست دل صبر نہ کر سکا اور انہوں نے اعدائے حق کی مرضات و ہوا کی تسلیم و اطاعت سے مردانہ وار انکار کر دیا۔ فی الحقیقت انہوں نے علماء حق و سلف کی سنت زندہ کر دی اور علماء ہند کے لیے اپنی سنت حسنہ یادگار چھوڑ گئے۔ وہ اگرچہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی روحِ عمل موجود ہے اور اس کے لیے جسم کی طرح موت نہیں (۱۳۶)۔
شیخ الہندؒ کی فراست
جمعیۃ علماء ہند کا دوسرا سالانہ اجتماع ۱۹، ۲۰، ۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء کو دہلی میں شیخ الہندؒ کی وفات سے ایک ہفتہ قبل ہوا تھا۔ صدارت شیخ الہندؒ کی تھی جبکہ ۵۰۰ سے زائد علماء نے اس میں شرکت کی تھی۔ اس اجتماع کا اہم مسئلہ امیر الہند کا انتخاب تھا۔ شیخ الہند اس انتخاب کے لیے ازحد بے چین تھے اور چاہتے تھے کہ یہ انتخاب اسی موقعہ پر کر لیا جائے۔ مولانا عبد الصمد رحمانی صاحب لکھتے ہیں کہ
’’وہ لوگ جو اس میں شریک تھے جانتے ہیں کہ اس وقت شیخ الہندؒ ایسے ناساز تھے کہ حیات کے بالکل آخری دور سے گزر رہے تھے، نقل و حرکت کی بالکل طاقت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اصرار تھا کہ اس نمائندہ اجتماع میں جبکہ تمام اسلامی ہند کے ذمہ دار اور اربابِ حل و عقد جمع ہیں، امیر الہند کا انتخاب کر لیا جائے اور میری چارپائی کو اٹھا کر جلسہ گاہ میں لے جایا جائے، پہلا شخص میں ہوں گا جو اس امیر کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔‘‘ (ص ۱۳۱)
امیر الہند کون؟
کتاب کے مرتب ابو سلمان شاہجہانپوری آغاز میں ہی جب شیخ الہندؒ کا ذکر مستقل باب میں کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی یہ تحریر قاری کے سامنے آتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ
’’تحریک کے امیر کی حیثیت سے شیخ الہند کو پیش کیا گیا ہے۔ بلاشبہ تحریک کے داعی کی حیثیت اور تحریک کی بنیادی اور اہم شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی لیکن ہندوستان کی امارتِ شرعیہ کی ذمہ داری کے لیے مولانا آزاد کی نگاہِ انتخاب حضرت ہی پر پڑی تھی اور حضرت نے اسے قبول فرما لیا تھا، اس لیے امام الہند کی حیثیت میرے نزدیک شیخ الہند کی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں اپنی نازک صحت کی بنا پر اپنے تئیں حضرت نے اس ذمہ داری سے الگ کر لیا تھا اور مولانا آزاد پر اپنا اعتماد فرما دیا تھا۔‘‘ (ص ۱۰۸)
قرآنِ کریم میں تکرار و قصص کے اسباب و وجوہ
مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ
عرب کے لوگ اکثر مشرک و بت پرست تھے اور خداوند کی توحید اور انبیاء کی نبوت اور قیامت کے آنے کا بالکل انکار کرتے تھے اور ان میں سے بعض کچھ افراط و تفریط کرتے تھے، اس لیے قرآن کے اندر مذکورہ تینوں امور کا بکثرت ذکر آیا ہے نیز تکرار و قصص کے اور بھی کئی اسباب ہیں۔
سبب اول
یہ کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اس لیے ان میں ان قصص کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، کہیں طویل اور کہیں مختصر، اور ہر جگہ ان کو بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر رکھا اور پچھلی دفعہ سے زیادہ لطف مہیا کیا۔ یعنی اگر قرآن بشر کا کلام ہوتا تو اس بات سے عاری ہوتا (گویا یہ امر اعجازِ قرآن کی دلیل ہے)۔
سبب دوم
یہ کہ مخالفین کو صاف کہا گیا تھا کہ اگر تم کو کچھ شک ہو تو ایک ہی سورت کی مقدار ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ تو احتمال تھا کہ وہ کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو الفاظ آتے تھے ان کو اس نے استعمال کر لیا (یعنی اس کو اور الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے لہٰذا کلامِ الٰہی نہیں ہے)۔ یا یہ کہتے کہ ہر ادیب کا اندازِ بیاں جدا جدا ہوتا ہے، اگر ہم ایک کا انداز اپنا نہیں سکے تو کیا ہوا؟ (یعنی اس (محمدؐ) نے بھی ایک ہی طریقہ اپنایا ہے جو دوسرے ادیبوں سے جدا ہے، تو اگر ہم ایک ہی طریقہ نہ اپنا سکے تو کیا قیامت آن پڑی۔ لیکن قرآن کریم میں قصص کو مختلف اندازوں میں بیان کرنے سے رفع ہو گیا۔ یا یہ کہتے یہ قصہ ہے اور قصص میں بلاغت کا دائرہ تنگ ہوتا ہے اور اس نے ایک دفعہ اس کو جو بلاغت سے بیان کیا ہے سو اتفاقاً ہوا ہے ورنہ ایسا اور الفاظ میں بیان نہ کر سکے گا۔ لیکن جب تکرارِ قصص ظاہر ہوا اور اندازِ بیان میں تشتت واقع ہوا تو ان تینوں اعتراضات کی جگہ نہ رہی۔
سبب سوم
یہ ہے کہ بعض اوقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم مخالف کی شرارت اور ایذاء سے ملول ہو جاتے تھے۔ سورہ حجر میں ہے:
وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّکَ یَضِیْقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُوْلُوْنَ۔ (آیت ۹۷)
ترجمہ: ’’اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں سے‘‘۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان قصص کو نقل فرماتے ہیں۔ سورۂ ہود میں ہے:
وَکُلًّا نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ اَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِہٖ فُؤَادَکَ وَجَآءَکَ فِیْ ھٰذِہِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَۃً وَّذِکْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ۔ (آیت ۱۲۰)
ترجمہ: ’’ہم آپ پر جتنے بھی قصے انبیاء کے بیان کرتے ہیں سو اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور اس میں آپ کو حق بات ملی ہے اور مؤمنوں کے واسطے نصیحت‘‘۔
اس لیے اکثر مقامات پر وقت موجود کے مناسب اسی قدر نقل ہوتا ہے جو تسلی کے لیے کافی ہو اور کچھ نہ کچھ سابقہ ذکر زیادہ مذکور ہوتا ہے۔
سبب چہارم
یہ ہے کہ گزرے ہوؤں کا حال آنے والوں کے لیے نصیحت قبول کرنے اور عبرت پکڑنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اکثر جگہوں میں مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں اور منکرین کو عبرت دلاتے ہیں۔ جب مومنوں کو کافروں کے ہاتھوں سے اذیت پہنچتی ہے یا جب کوئی گروہ نیا نیا مسلمان ہوتا ہے تو ان قصوں میں سے کسی کا نقل کرنا مناسب حال ہوتا ہے تو ان کی نقل ظہور پذیر ہوتی ہے۔
(از ازالۃ الشکوک ج ۱ ص ۱۳۲ تا ۱۳۴)
انتخاب و تسہیل: حافظ محمد عمار خان ناصر
بعثتِ نبویؐ کے وقت ہندو معاشرہ کی ایک جھلک
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی وہ بابرکت زمین ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوا تھا۔ گویا اس لحاظ سے ہندوستان کی زمین وہ اشرف قطعہ ہے جس کو سب سے پہلے نبیؑ کے مبارک قدموں نے روندا جس پر ہزارہا سال گزر چکے تاآنکہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور نزدیک ہوا۔ اس وقت سرزمینِ ہند میں بدکرداری، اخلاقی پستی اور دنارت کا یہ عالم تھا کہ مندروں کے محافظ اور مصلحینِ قوم بداخلاقی کا سرچشمہ تھے جو ہزاروں اور لاکھوں ناآزمودہ کار لوگوں کو مذہب کے نام اور شعبدہ بازی کے کرشموں سے خوب لوٹتے اور مزے سے عیش اڑاتے تھے (آر سی دت ج ۴ ص ۲۸۳)۔ راجوں اور مہاراجوں کے محلات میں بادہ نوشی کثرت سے رائج تھی اور رانیاں حالتِ خمار میں جامۂ عصمت و ناموس اتار ڈالتی تھیں (ایضاً ص ۳۴۳)۔ سڑکوں اور شاہراہوں پر آوارہ گرد اور جرائم پیشہ افراد کا ہر وقت مجمع لگا رہتا تھا (ایضاً ص ۴۶۹)۔
اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی شریف انسان اور خصوصیت سے باحیا عورتوں کا وہاں سے گزرنا وبالِ جان سے کم نہ تھا اور ہر وقت جان و عزت کا خطرہ درپیش رہتا تھا۔ دیوداسیوں اور عورتوں کی بداخلاقی اور جنسی جنون کی دل سوز حرکات اور حالات پڑھنے اور سننے سے بھی شرم محسوس ہوتی ہے اور کوئی شریف اور باحیا انسان ان کو پڑھ کر اپنے نفس کو آمادہ نہیں پاتا الّا یہ کہ دل پر جبر کر کے پڑھے تو اور بات ہے (ملاحظہ ہو سفرنامہ ابوزیدؒ ص ۱۳۰ اور احسن تقاسیم مقدسیؒ ص ۴۸۳)
جوا اس حد تک رائج تھا کہ سونے اور چاندی کے سکے اور زیورات کا تو کیا کہنا، عورتیں بھی جوئے میں ہاری جاتی تھیں اور ازدواجی تعلقات میں ایسی بے راہ روی اختیار کر لی گئی تھی کہ ایک ایک عورت کے کئی کئی شوہر ہوتے تھے۔ اور ان کی روحانیت کا یہ حال تھا کہ بعض فرقوں میں عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا کر کے ان کی شرمگاہوں کی پوجا کرتے تھے (ستیارتھ پرکاش سمولاس گیارہ ص ۳۶۷ طبع لاہور)۔ شاید وہ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ شرمگاہ ہی دنیا کی جڑ اور منبع نسلِ انسانی ہے لہٰذا اس بابرکت اور کثیر المنفعت چیز کی پوجا کیوں نہ ہو؟ اور ایسے مردوں اور عورتوں کے ان کے نزدیک خاص القاب ہوتے تھے، چنانچہ لکھا ہے کہ
’’اور جب کسی عورت یا دیشیا کو یا کسی مرد کو ننگا کر کے اور ان کے ہاتھ میں تلوار کر ان کی جائے نہانی کی پرستش کرتے ہیں تو عورت کا نام دیوی اور مرد کا نام مہادیو رکھتے ہیں۔‘‘ (ستیارتھ پرکاش ص ۳۶۸)
شوہر کے مرنے پر بعض عورتوں کو خود ان کے باپ اور بھائی اعزہ و اقارب زندہ نذرِ آتش کر دیتے تھے اور اس شنیع کارروائی کو اپنی اصطلاح میں وہ ’ستّی‘‘ کہتے تھے۔ اور اس کی حکمت اور فلسفہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ عورت اپنے خاوند کے فراق کو گوارہ نہیں کر سکتی اور اس کی محبت و الفت میں اپنی جانِ عزیز کو اس پر قربان کر دینے کے لیے بطیب خاطر رضامند ہے۔ ممکن ہے بعض شوریدہ سر عورتیں اس قومی اور آبائی رسم کی وجہ سے اس کو قربانی ہی تصور کرتی ہوں مگر حتی الوسع موت کو کون پسند کرتا ہے؟ ان کی اس ظالمانہ رسم کا بعض مسلمان اور خدا رسیدہ صوفی شاعروں نے بھی تذکرہ کیا ہے، چنانچہ حضرت امیر خسروؒ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ؎
خسروا در عشق بازی کم زہندو زن مباش
کز برائے مردہ می سوزند جان خویش را
اور جناب بیدل پشاوریؒ یوں کہتے ہیں کہ ؎
باتو میگویم مباش اے سادہ دل ہندو پسر
در طریق جاں سپاری کم زہندو دخترے
اور برہمنوں نے اپنی قلبی تسکین اور سہولت کے لیے یہ چند نفس پسند قوانین وضع کئے اور تراشے تھے:
- برہمن کو کسی حالت میں خواہ وہ کتنے ہی سنگین جرائم کا مرتکب رہ چکا ہو، سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔
- کسی اونچی ذات کا مرد اگر کسی نیچی ذات کی عورت سے زنا کرے تو کوئی حرج نہیں۔
- کسی بودھ راہبہ تک کی عصمت دری کی سزا میں معمولی جرمانہ کافی ہے۔
- اگر کوئی اچھوت ذات کا شخص کسی اعلیٰ ذات والے کو چھو لے اور ہاتھ لگا دے تو اس کی سزا موت ہے۔
- اگر کوئی نیچی ذات والا اپنے سے اونچی ذات والے کو مارے تو اس کے اعضاء کاٹ دیئے جائیں، اور اگر اس کو گالی دے تو اس کی زبان قطع کر دینی چاہیئے، اور اگر اسے تعلیم دینے کا دعوٰی کرے تو گرم تیل اس کے منہ میں ڈالنا چاہیئے (آرسی دت کی قدیم ہندوستان ص ۳۴۲)
یہ اصول و ضوابط اور قوانین تھے اہلِ ہند کے جس میں اچھوت اقوام کے لیے خیرخواہی کا ادنٰی جذبہ اور ان کی ہمدردی کا ایک حرف بھی موجود نہ تھا۔ جو بزبانِ حال شاید برہمنوں کے ان خودساختہ ملکی اور قومی قوانین پر آنسو بہاتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے ؎
تم جو دیتے ہو نوشتہ وہ نوشتہ کیا ہے
جس میں ایک حرفِ وفا بھی کہیں مذکور نہیں
امامِ عزیمت امام احمد بن حنبلؒ اور دار و رَسَن کا معرکہ
مولانا ابوالکلام آزاد
تیسری صدی کے اوائل میں جب فتنۂ اعتزال و تعمق فی الدین اور بدعۃ مضلۂ تکلم یا مفلسفہ والحراف از اعتصام بالسنہ نے سر اٹھایا، اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ لگاتار تین عظیم الشان فرمانرواؤں یعنی مامون، معتصم اور واثق باللہ کی شمشیر استبداد و قہر حکومت نے اس فتنہ کا ساتھ دیا، حتٰی کہ بقول علی بن المدینی کے فتنۂ ارتداد و منع زکوٰۃ (بعہد حضرت ابوبکرؓ) کے بعد یہ دوسرا فتنۂ عظیم تھا جو اسلام کو پیش آیا۔ تو کیا اس وقت علماء امت اور ائمہ شریعت سے عالمِ اسلام خالی ہو گیا تھا؟ غور تو کرو کیسے کیسے اساطین علم و فن اور اکابر فضل و کمال اس عہد میں موجود تھے؟ خود بغداد علماء اہل سنت و حدیث کا مرکز تھا مگر سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے عزیمۃ دعوۃ و کمال مرتبۂ وراثت نبوت و قیام حق و ہدایت فی الارض والامۃ کا وہ جو ایک مخصوص مقام تھا صرف ایک ہی قائم لامر اللہ کے حصہ آیا یعنی سید المجددین امام الصالحین حضرت امام احمد بن حنبلؒ۔
اپنے اپنے رنگ میں سب صاحب مراتب و مقام تھے لیکن اس مرتبہ میں تو اور کسی کا سانجھا نہ تھا کہ قیام سنت و دین خالص کا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہونے والا تھا اور مامون و معتصم کے جبر و قہر اور بشر مریسی اور قاضی ابنِ ابی داؤد جیسے جبابرہ معتزلہ کے تسلط و حکومت نے علماء حق کے لیے صرف دو ہی راستے باز رکھے تھے۔ یا اصحاب بدعۃ کے آگے سر جھکا دیں اور مسئلہ خلقِ قرآن پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے اس کی نظیر قائم کریں کہ شریعت میں صرف اتنا ہی نہیں ہے جو رسولؐ بتلا گیا بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور ہر ظن کو اس میں دخل ہے، ہر رائے اس پر قاضی و امر ہے، ہر فلسفہ اس کا مالک و حاکم ہے ’’یفعل ما یشاء و یختار‘‘ ۔ اور یا پھر قید خانے میں رہنا، ہر روز کوڑوں سے پیٹا جانا اور ایسے تہ خانوں میں قید ہو جانا کہ ’’لا یرون فیہ الشمس ابدا‘‘ کو قبول کر لیں۔
بہتوں کے قدم تو ابتدا ہی میں لڑکھڑا گئے۔ بعضوں نے ابتدا میں استقامت دکھلائی لیکن پھر ضعف و رخصت کے گوشے میں پناہ گیر ہو گئے۔ عبد اللہ بن عمر القواریری اور حسن بن عماد امام موصوف کے ساتھ ہی قید کیے گئے تھے مگر شدائد و محن کی تاب نہ لا سکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے۔ بعضوں نے روپوشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی کہ کم از کم اپنا دامن تو بچا لے جائیں۔ کوئی اس وقت کہتا تھا ’’لیس ھذا زمان بکاء تضرع و دعا کدعاء الغریق‘‘ یعنی یہ زمانہ درسو اشاعت علوم و سنت کا نہیں ہے یہ تو وہ زمانہ ہے کہ بس اللہ کے آگے تضرع و زاری کرو اور ایسی دعائیں مانگو جیسی سمندر میں ڈوبتا ہوا شخص دعا مانگے۔ کوئی کہتا تھا ’’احفظوا السانکم دعا لجوا قلبکم و خذوا ما تعرفوا و دعوا ما تنکروا‘‘ اپنی زبانوں کی نگہبانی کرو، اپنے دل کے علاج میں لگ جاؤ، جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کیے جاؤ اور جو برا ہو اس کو چھوڑ دو۔ کوئی کہتا ’’ھذا زمان السکوت و ملازمۃ البیوت‘‘ یہ زمانہ خاموشی کا زمانہ ہے اور اپنے اپنے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ رہنے کا۔
جبکہ تمام اصحابِ کار و طریق کا یہ حال ہو رہا تھا اور دین الخالص کا بقا و قیام ایک عظیم الشان قربانی کا طلب گار تھا تو غور کرو کہ صرف امام موصوفؒ ہی تھے جن کو فاتح و سلطان عہد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نہ تو دعاۃ فتن و بدعۃ کے آگے سر جھکایا نہ روپوشی و خاموشی و کنارہ کشی اختیار کی اور نہ بند حجروں کے اندر کی دعاؤں اور مناجاتوں پر قناعت کر لی بلکہ دین خالص کے قیام کی راہ میں اپنے نقش و وجود کو قربان کر دینے اور تمام خلف امت کے لیے ثبات و استقامت علی السنۃ کی راہ کھول دینے کے لیے بحکم ’’فاصبر اولو العزم من الرسل‘‘ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں چلے گئے۔ چار چار بوجھل بیڑیاں پاؤں میں ڈالی گئیں۔ پہن لیں۔ اسی عالم میں بغداد سے طرطوس لے چلے اور حکم دیا گیا کہ بلا کسی کی مدد کے خود ہی اونٹ پر سوار ہوں اور خود ہی اونٹ سے اتریں۔ اس کو بھی قبول کر لیا۔ بوجھل بیڑیوں کی وجہ سے ہل نہیں سکتے تھے، اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے۔
عین رمضان المبارک کے عشرہ اخیر میں، جس کی طاعت اللہ کو تمام دنوں کی طاعات سے زیادہ محبوب ہے، بھوکے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے، اور اس پیٹھ پر جو علوم و معارفِ نبوت کی حامل تھی لگاتار کوڑے اس طرح مارے گئے کہ ہر جلاد دو ضربیں پوری قوت سے لگا کر پیچھے ہٹ جاتا اور پھر نیا تازہ دم جلاد اس کی جگہ لے لیتا۔ اس کو بھی خوشی خوشی برداشت کر لیا مگر اللہ کے عشق سے منہ نہ موڑا اور راہِ سنت سے منحرف نہ ہوئے۔ تازیانے کی ہر ضرب پر بھی جو صدا زبان سے نکلتی تھی وہ نہ تو جزع و فزع کی تھی اور نہ شور و فغاں کی، بلکہ وہی تھی جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا یعنی ’’القرآن کلام اللہ غیر مخلوق‘‘۔ اللہ اللہ یہ کیسی مقام دعوۃ کبرٰی کی خسروی و سلطانی تھی اور وراثۃ و نیابۃ نبوۃ کی ہیبت و سطوۃ کہ خود المعتصم باللہ، جس کی ہیبت و رعب سے قیصر روم لرزاں و ترساں رہتا تھا، سر پر کھڑا تھا، جلادوں کا مجمع چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا ’’یا احمد! واللہ انی علیک الشفیق، وانی لا شفق علیک کشفقتی علی ھارون ابنی و واللہ لئن اجابنی لا طلقن عنک بیدی ما تقول‘‘ یعنی واللہ میں تم پر اس سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہوں جس قدر اپنے بیٹے کے لیے شفیق ہوں، اگر تم خلق قرآن کا اقرار کر لو تو قسم خدا کی ابھی اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں۔
لیکن اس پیکر حق، اس مجسمۂ سنت، اس موید بالروح القدس، اس صابر اعظم کما صبر اولوالعزم من الرسل کی زبان صدق سے صرف ہی جواب نکلتا تھا ’’اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنۃ رسولہ حتٰی اقول بہ‘‘ اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کے رسول کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں۔ اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا ؎
چو غلام آفتابم ز آفتاب گویم
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
اگر اس چراغ تجدید و مصباح عزیمۃ دعوۃ کی روشنی مشکوٰۃ نبوۃ سے مستمیز نہ تھی تو پھر یہ کیا تھا کہ جب معتصم ہر طرح عاجز آ کر قاضی ابن ابی داؤد وغیرہ علماء بدعت و اعتزال سے کہتا ’’ناظر و کلموہ‘‘ اور وہ کتاب و سنت کے میدان میں عاجز آ کر اپنے اوہام و ظنون باطلہ کو باسم عقل و رائے پیش کرتے کہ سر تا سر بونانیات ملعونہ سے ماخوذ تھے تو وہ اس کے جواب میں بے ساختہ بول اٹھتے ’’ما ادری ما ھذا؟‘‘ میں نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے ’’اعطونی شیئًا من کتاب اللہ او من سنۃ رسولہ حتی اقول‘‘۔ اس تمام کائنات ہستی میں میرے سر کو جھکانے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس کے سوا نہ میرے لیے کوئی دلیل ہے نہ علم۔
امام موصوفؒ کو جب قید کر کے طرطوس روانہ کیا گیا تو ابوبکر الاحول نے پوچھا ’’ان عرضت علیک السیف تجیب؟‘‘ اگر تلوار کے نیچے کھڑے کر دیے گئے تو کیا اس وقت مان لو گے؟ کہا، نہیں۔ ابراہیم بن مصعب کوتوال کہتا ہے کہ میں نے کسی انسان کو بادشاہوں کے آگے احمد بن حنبلؒ سے بڑھ کر بے رعب نہ پایا۔ ’’یومیذ ما نحن فی عینیہ الّا کامثال الذباب‘‘ ہم عمال حکومت ان کی نظروں میں مکھیوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے تھے اور یہ بالکل حق ہے۔ جن لوگوں کی نظروں میں جلالِ الٰہی سمایا ہو وہ مٹی کی ان پتلیوں کو، جنہوں نے لوہا تیز کر کے کاندھے پر ڈال رکھا ہے یا بہت سا سونا چاندی اپنے جسم پر لپیٹ لیا ہے، کیا چیز سمجھتے ہیں؟ ان کو تو خود اقلیمِ عشقِ الٰہی کی سروری و شاہی اور شہرستان صدق و صفا کا تاج و تخت حاصل ہے۔
ابوالعباس الرتی سے حافظ ابن جوزیؒ روایت کرتے ہیں کہ جب رقہ میں امام موصوف قید تھے تو علماء کی ایک جماعت گئی اور اس قسم کی روایت و نقول سنانے لگی جن سے بخوفِ جان تقیہ کر لینے کی رخصت نکلتی ہے۔ امام موصوف نے سب سن کر جواب دیا ’’کیف تضعون بحدیث جناب؟ ان من کان قبلکم کان ینشر احدھم بالمنشا رثم لا یصدر ذالک عن دینہ۔ قالوا فیئسنا منہ‘‘ یعنی یہ تو سب کچھ ہوا مگر بھلا اس حدیث کی نسبت کیا کہتے ہو کہ جب صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مظالم و شدائد کی شکایت کی تو فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے سروں پر آرا چلایا جاتا تھا اور جسم لکڑی کی طرح چیر ڈالے جاتے تھے مگر یہ آزمائشیں بھی ان کو حق سے نہیں پھرا سکتی تھیں۔ ابوالعباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو مایوس ہو کر چلے آئے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے، یہ اپنی بات سے پھرنے والے نہیں۔
یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عزیمۃ دعوۃ، عزیمۃ دعوۃ تو یہ ہے عزیمۃ دعوۃ اور یہ ہے وراثت و نیابت مقام ’’فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل‘‘ کا اور یہ ہے ان ایام فتن کا صبر اعظم و اکبر جن کی نسبت ترمذی کی روایت میں فرمایا ’’الصبر فی ھن کالقبض علی البحمر‘‘ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اگر چاہیں تو گوشہ رخصت و بیچارگی میں امن و عافیت کے پھول چن سکتے ہیں لیکن وہ پھولوں کو چھوڑ کر دہکتے ہوئے انگارے پکڑ لیتے ہیں اور اسی لیے ان کا اجر و ثواب بھی ’’مثل اجر خمسین رجلاً یعملون مثل عملکم‘‘ کا حکم رکھتا ہے۔
مانا کہ ضعیفوں اور درماندوں کے لیے رخصت و گلوخلاصی کی راہیں بھی باز رکھی گئی ہوں لیکن اصحابِ عزائم کا عالم دوسرا ہے، ان کی ہمت عالی بھلا میدان عزیمۃ و اسبقیۃ بالخیرات کو چھوڑ کر تنگنائے رخصت و ضعف میں پناہ لینا کب گوارہ کر سکتی ہے؟ جوانانِ ہمت اور مردانِ کارزار اس ننگ کو کیوں قبول کرنے لگے کہ کمزوروں اور درماندوں کی لکڑی کا سہارا پکڑیں؟ جن کے لیے اس میں سلامتی ہے ہوا کرے گی مگر ان کے لیے تو ایسا کرنا ہمت کی موت ہے، ایمان کی پامالی ہے اور عشق کی جبینِ عزت کے لیے داغ ننگ و عار سے کم نہیں۔ ’’حسنات الابرار سیئات المقربین‘‘ رخصۃ و عزیمۃ کی تفریق اور اعلیٰ و ادنٰی کا امتیاز اصحابِ عمل کے لیے ہے نہ کہ اصحابِ عشق کے لیے۔ عشق کی راہ ایک ہی ہے اور اس میں جو کچھ ہے عزیمۃ ہی عزیمۃ ہے۔ ضعف و بیچارگی کا تو ذکر ہی کیا، وہاں رخصت کا نام لینا بھی کم از معصیت نہیں ؎
ملتِ عشق از ہمہ دین ہا جداست
عاشقاں را مذہب و ملّت خداست
ضرب تازیانہ کے لیے حکم دیا تو وہ علماء اہل سنت بھی دربار میں موجود تھے جو شدۃِ محن و مصائب کی تاب نہ لا سکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے۔ ان میں سے بعض نے کہا ’’من صنع من اصحابک فی ھذا لامر ما تصنع‘‘ خود تمہارے ساتھیوں میں سے کس نے ایسی ہٹ کی جیسی تم کر رہے ہو؟ امام احمدؒ نے کہا، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی ’’اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنۃ رسولہ حتی اقول بہ‘‘۔ عین حالتِ صوم میں کہ صرف پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ رکھ لیا تھا تو تازہ دم جلادوں نے پوری قوت سے کوڑے مارے یہاں تک کہ تمام پیٹھ زخموں سے چور ہو گئی اور تمام جسم خون سے رنگین ہو گیا۔
خود کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو چند آدمی پانی لائے اور کہا پی لو مگر میں نے انکار کر دیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ وہاں سے مجھ کو اسحاق بن ابراہیم کے مکان میں لے گئے، ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ابن سماعہ نے کہا، تم نے نماز پڑھی حالانکہ خون تمہارے کپڑوں میں بہہ رہا ہے؟ یعنی دم جاری و کثیر کے بعد طہارت کہاں رہی؟ میں نے جواب دیا ’’قل صلی عمر وجرحہ یثعب دما‘‘ ہاں مگر میں نے وہی کیا جو حضرت عمرؓ نے کیا تھا، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور قاتل نے زخمی کیا مگر اسی حالت میں انہوں نے نماز پوری کی۔
ابن سماعہ کے جواب میں حضرت امامؒ نے حضرت عمرؓ کی جو نظیر پیش کی تو یہ ان کی تسلی کے لیے بس کرتی تھی، مگر میں کہتا ہوں کہ جو خون اس وقت امام احمد بن حنبلؒ کے زخموں سے بہہ رہا تھا گر وہ خون ناپاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا میں اور کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کو پاک کر سکتی ہے اور کون سا پانی ہے جو طاہر و مطہر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو دنیا کی تمام پاکیاں اس ناپاکی پر قربان! اور دنیا کی ساری طہارتیں اس پر سے نچھاور۔ یہ کیا بات ہے کہ پاک سے پاک اور مقدس سے مقدس انسان کی میت کے لیے بھی غسل ضروری ٹھہرا مگر شہیدانِ حق کے لیے یہ بات ہوئی کہ ان کی پاکی شرمندۂ آب غسل نہیں ’’لم یصل علیھم ولم لیغسلھم‘‘ بلکہ ان کے خون میں رنگے ہوئے کپڑوں کو بھی ان سے الگ نہ کیجئے۔ ’’یدفنوا فی ثیابھم ودمائھم‘‘ اور اسی لباس میں گلگوں و خلعت رنگین میں وہاں جانے دیجئے جہاں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جہاں خون و عشق کے سرخ دھبوں سے بڑھ کر شاید اور کوئی نقش و نگار عمل مقبول و محبوب نہیں۔ ’’عند ربھم یرزقون۔ فرحین بما اٰتاھم اللہ‘‘ ؎
خونِ شہیداں راز آب اولی تر است
ایں گناہ از حد ثواب اولی تر است
اللہ اللہ! یہاں طہارتِ جسم و لباس کا کیا سوال ہے؟ امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی تمام عمر میں اگر کوئی پاک سے پاک اور سچی سے سچی نماز پڑھی تھی تو یقیناً وہ وہی ظہر کی نماز تھی۔ ان کی تمام عمر کی وہ نمازیں ایک طرف جو دجلہ کے پانی سے پاک کی گئی تھیں، اور وہ چند گھڑیوں کی عبادت ایک طرف جس کو راہِ ثبات حق میں بہنے والے خون نے مقدس و مطہر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ! جس کے عشق میں چار چار بوجھل بیڑیاں پاؤں میں پہن لی تھیں، جس کی خاطر سارا جسم زخموں سے چور اور خون سے رنگین ہو رہا تھا، اسی کے آگے جبینِ نیاز جھکی ہوئی! اسی کے ذکر میں قلب و لسان لذت یاب تسبیح و تحمید! اسی کے جلوۂ جمال میں چشمِ شوق وقف نظارہ و دید! اور اسی کی یاد میں روح مضطر محو سرشار عشق و خود فراموشی!
؏ یوں عبادت ہو تو زاہد ہیں عبادت کے مزے
امام موصوف کے لڑکے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے ’’رحم اللہ ابا الھیثم اغفر اللہ لابی الھیثم‘‘ خدا ابو الہیثم پر رحم کرے، خدا ابوالہیثم کو بخش دے۔ میں نے ایک دن پوچھا، ابوالہیثم کون ہے؟ کہا جس دن مجھ کو سپاہی دربار میں لے گئے اور کوڑے مارے گئے تو جب ہم راہ سے گزر رہے تھے ایک آدمی مجھ سے ملا اور کہا مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں مشہور چور اور عیار ابوالہیثم حداد ہوں۔ میرا نام شاہی دفتر میں ثبت ہے، بارہا چوری کرتے پکڑا گیا اور بڑی بڑی سزائیں جھیلیں۔ صرف کوڑوں کی ہی مار اگر گنوں تو سب ملا کر اٹھارہ ہزار ضربیں تو میری پیٹھ پر ضرور پڑی ہوں گی۔ با ایں ہمہ میری استقامت کا یہ حال ہے کہ اب تک چوری سے باز نہیں آیا جب کہ کوڑے کھا کر جیل خانے سے نکلا، سیدھا چوری کی تاک میں چلا گیا۔ میری استقامت کا یہ حال شیطان کی طاعت میں رہا ہے دنیا کی خاطر۔ افسوس تم پر اگر اللہ کی محبت کی راہ میں اتنی استقامت بھی نہ دکھا سکو اور دین حق کی خاطر چند کوڑوں کی ضرب برداشت نہ کر سکو۔ میں نے جب یہ سنا تو اپنے جی میں کہا اگر حق کی خاطر اتنا بھی نہ کر سکے جتنا دنیا کی خاطر ایک چور اور ڈاکو کر رہا ہے تو ہماری بندگی پر ہزار حیف اور ہماری خدا پرستی سے بت پرستی لاکھ درجہ بہتر ؏
منہ منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز
اے روسیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
مامون و معتصم اور الواثق نے جو کچھ کیا وہ معلوم ہے۔ جعفر المتوکل کا یہ حال ہے کہ اس کی خلافت بدعت و اربابِ بدعت کے زوال و خسران اور سنت و اصحابِ حدیث کے امن و عروج کا اعلانِ عام تھی۔ حافظ ابن جوزیؒ لکھتے ہیں کہ متوکل باللہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا کہ کسی طرح پچھلے مظالم کی تلافی کرے۔ ایک بار اس نے بیس ہزار سکے بھیجے اور دربار میں بلایا۔ ایک بار ایک لاکھ درہم بھیجا اور سخت اصرار کیا کہ اس کو قبول کر لیجئے لیکن ہر مرتبہ امام موصوف نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کشت کاری کر لیتا ہوں جو میری ضروریات کے لیے کافی ہے، اس بوجھ کو اٹھا کر کیا کروں گا۔ کہا گیا کہ اپنے لڑکے کو حکم دیجئے وہ قبول کر لیں۔ فرمایا وہ اپنی مرضی کا مختار ہے۔ لیکن جب عبد اللہ سے کہا گیا تو انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر لانے والوں نے کہا کہ خود نہیں رکھنا چاہتے تو امیر المومنین کا حکم ہے قبول کر لیجئے اور فقراء اور مساکین کو بانٹ دیجئے۔ فرمایا میرے دروازے سے زیادہ امیر المومنین کے محل کے نیچے فقیروں کا مجمع رہتا ہے، فقیروں کو ہی دینا ہے تو وہیں دے دیا جائے۔ اس ہنگامے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ اسحاق بن ابراہیم کے سخت اصرار سے دس ہزار درہم لے لیے تو اسی وقت مہاجرین و انصار کی اولاد میں تقسیم کر دیے۔ ان کے لڑکے راوی ہیں کہ جب خلیفہ متوکل ان کی تعظیم و تکریم میں حد درجہ غلو کرنے لگا تو انہوں نے کہا ’’ھذا امر اشد علٰی من ذلک، ذلک فتنۃ الدین وھذا فتنۃ الدنیا‘‘ یہ معاملہ تو گزشتہ معاملے سے بھی کہیں زیادہ میرے لیے سخت ہے، وہ دین کے بارے میں فتنہ تھا اور یہ فتنہ دنیا ہے۔
یعنی مصائب و محن کی آزمائش کہیں زیادہ پُراَمن ہے بمقابلہ آزمائش افیم دنیا و دعوۃ طمع و ترغیب کے۔ اور یہ بالکل حق ہے۔ کتنے ہی شہسواران ثبات و استقامت ہیں جو پہلے میدانِ آزمائش سے تو صحیح و سلامت نکل گئے مگر دوسری راہ سامنے آئی تو اول قدم ہی ٹھوکر لگی۔ حالانکہ مردِ کامل وہ ہے جس پر ’’یدعون ربھم خوفاً و طمعاً‘‘ کا مقام ایسا طاری ہو جائے کہ دنیا کا خوف اور دنیا کی طمع دونوں قسم کے حربے اس کے لیے بالکل بیکار ہو جائیں۔
مرسلہ: قاری قیام الدین الحسینی
مولانا آزادؒ کا سنِ پیدائش ۔ ایک حیرت انگیز انکشاف
دیوبند ٹائمز
خدا بخش لائبریری پٹنہ کی ریسرچ فیلو شائستہ خان نے اپنی ریسرچ کے ذریعے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ۱۸۸۵ء میں پیدا ہوئے تھے جبکہ آج تک ان کی پیدائش کا سال ۱۸۸۷ء بتایا جا رہا ہے۔ شائستہ خان نے تحقیق کے دوران مولانا آزاد کا انہی کی تحریر میں لکھا ہوا ایک خط دریافت کیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ۱۸۸۵ء کانگریس کا سال پیدائش بھی ہے اور شائستہ خان نے یہ دھماکہ اس وقت کیا ہے جب مولانا آزادؒ کے یومِ ولادت کی صدی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔
خدا بخش لائبریری میں مولانا آزاد پر جو سیمینار منعقد ہوا تھا اس میں اپنا مقالہ پڑھتے ہوئے شائستہ خان نے یہ انکشاف کر کے حاضرین کو چونکا دیا۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اپنے ایک عزیز دوست یوسف رنجور (پٹنہ) کو لکھا تھا۔ رنجور کا تعلق پٹنہ کے اس صدیقی خاندان سے تھا جو جنگِ آزادی میں ہمیشہ پیش پیش رہا۔ یہ خاندان اس صدی کے شروع میں کلکتہ میں جا بسا تھا اور رنجور صاحب کو کلکتہ ہی میں مولانا خطوط لکھا کرتے تھے۔ رنجور کو مولانا نے جولائی ۱۹۰۳ء میں خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنی پیدائش کی تاریخ ۱۳۰۳ھ بتائی ہے جو ۱۸۸۵ء یا ۱۸۸۶ء کے ابتدائی ماہ ہو سکتے ہیں۔
شائستہ خان مولانا آزادؒ کی سوانح لکھ رہی ہیں جس میں کئی نئے اور نہاں گوشوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس خط سےمولانا آزادؒ کی والدہ کے انتقال کی صحیح تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کی بہنوں کے صحیح نام کیا تھے۔ شائستہ خان نے دعوٰی کیا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں کئی ایسی کتابیں فروخت ہو رہی ہیں جو مولانا آزادؒ کی لکھی ہوئی بتائی جا رہی ہیں حالانکہ عبد الرزاق صاحب ملیح آبادی نے ان کتابوں کو تحریر کیا تھا۔ شائستہ نے مولانا کے کئی ایسے تحریری نسخے اور دستاویزات تلاش کیے ہیں جن سے ان کی زندگی پر نئی روشنی پڑتی ہے۔
مولانا آزاد کا یہ خط کئی زاویوں سے حد درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ اول تو یہ کہ مولانا نے اپنی سن پیدائش ۱۳۰۳ھ لکھی ہے۔ اپنی والدہ کا نام انہوں نے زینب لکھا ہے اور بہنوں کا خدیجہ، فاطمہ اور حنیفہ۔ مولانا نے اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی والدہ ان کی بہنوں کی شادیاں ان کے (آزاد کے) چچازاد بھائیوں سے کرنا چاہتی تھیں جو مکہ میں مقیم تھے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ مولانا آزاد کو اس کا بے حد قلق اور رنج رہا۔
(بشکریہ دیوبند ٹائمز)
کیا فرعون مسلمان ہو گیا تھا؟
شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
(امام الصوفیاء حضرت الشیخ محی الدین بن عربی قدس اللہ سرہ العزیز سے منسوب ایک قول میں دعوٰی کیا گیا ہے کہ فرعون نے جب غرق ہوتے وقت اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اظہار کیا تو اس کا ایمان قبول ہو گیا تھا اور وہ شہادت سے ہمکنار ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک استفسار کے جواب میں اس دعوٰی کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ ادارہ)
ایمانِ فرعون کے بارے میں جو کچھ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ جمہور کی رائے کے خلاف ہے۔ استدلال کی سخافت سے شبہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ قول ان کا نہیں بلکہ جیسا بعض علماء کا قول ہے کہ ملاحدہ نے ان کی کتاب میں اپنی طرف سے زیادہ کر دیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ملّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقالہ پر رد کے لیے ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے جس کو عرصہ ہوتا ہے، میں نے مدینہ منورہ زید شرفا میں دیکھا تھا، یہ نہیں معلوم کہ وہ چھپ گیا ہے یا نہیں۔
(۱) استدلال میں اولاً امراۃ فرعون رضی اللہ عنہا کا قول پیش کیا گیا ہے مگر یہ استدلال نہایت کمزور ہے۔ جس وقت یہ قول ان سے صادر ہوا جب تک وہ خود بھی ایمان نہیں لائی تھیں۔ پھر ان کا عالم الغیب ہونا یا امور مستقبلہ پر مطلع ہونا کسی وقت میں بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کا کشف و الہام کسی زمانے شرعی حجت ہو سکتا ہے، پھر کس طرح یہ قول قابلِ استدلال ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر محض ان کے قول کو نقل فرمایا ہے، اس کی تصحیح اور تصدیق نہیں فرمائی۔ یہ عادت اقوالِ صحیحہ اور باطلہ دونوں میں جاری ہے۔ نیز قرۃ العین ہونا محبوبیہ سے کنایہ ہے جو کہ ’’القیت علیک محبۃ منی‘‘ (اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے) کا نتیجہ تھا۔ اس لیے ہر مومن اور غیر مومن کے اس زمانہ طفولیت میں حضرت موسٰی علیہ السلام محبوب اور قرۃ عین تھے۔ اس سے ایمانِ فرعون پر استدلال نہایت ہی کمزور ہے، بالخصوص جبکہ اس کے خلاف قواعد کلیہ اور آیات جزئیہ دونوں کھلے بندوں دلالت کر رہی ہوں۔
علیٰ ہذا القیاس اس کو آیت قرار دینا بھی اسلام پر دال نہیں۔ ہر وہ شے جس سے جناب باری عز اسمہ کے صفات و افعال و ذات پر کسی وجہ سے استدلال ہو سکتا ہو، وہ آیۃ ہو سکتی ہے۔ اس میں ذی روح ہونے کی بھی شرط نہیں ہے چہ جائیکہ اسلام مشروط ہو۔
قواعدِ کلیّہ شرعیہ جو کہ قطعی طور پر اس کے بطلان کے شاہد ہیں
فلما رأوا بأسنا قالوا اٰمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین فلم یک ینفعھم ایمانھم لما رأوا بأسنا سنۃ اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ھنا لک الکافرون (سورہ مومن ۸۴ و ۸۵)
(ترجمہ) ’’پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو، بولے ہم یقین لائے اللہ اکیلے پر اور ہم نے چھوڑ دیں وہ چیزیں جن کو شریک بتلاتے تھے، پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کو یقین لانا ان کا جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب، رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں اور خراب ہوئے اس جگہ لشکر۔‘‘
اس آیت سے قاعدہ کلیہ اور سنتِ الٰہی کا پتہ چلتا ہے کہ عذابِ الٰہی کے دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:
فلما احسوا بأسنا اذا ھم منھا یرکضون لا ترکضوا وارجعوا الٰی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسئلون قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواھم حتی جعلناھم حصیدًا خامدین (سورہ انبیاء ۱۲۔۱۵)
(ترجمہ) ’’پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہماری آفت کی تب لگے وہاں سے بھاگنے، مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا اور اپنے گھروں میں شاید تم کو کوئی پوچھے، کہنے لگے ہائے خرابی ہماری ہم تھے گنہگار، پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے کاٹ کر بجھے پڑے ہوئے۔‘‘
دوسری جگہ ارشاد ہے:
فلولا کانت قریۃ اٰمنت فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس لما اٰمنوا کشفنا عنھم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناھم الی حین (سورہ یونس۹۸)
(ترجمہ) ’’سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی پھر کام آتا ان کو ایمان لانا، مگر یونس کی قوم جب وہ ایمان لائی اٹھا لیا ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگانی میں اور فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔‘‘
الغرض عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان لانا نفع دیتا۔ اس قاعدے کلیے سے صرف قوم یونس علیہ السلام کو مستثنٰی قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ حقیقتاً ان پر عذاب نہیں آیا تھا بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جلدبازی کی بنا پر صورتِ عذاب نمودار کی گئی تھی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام پر اس جلدبازی پر متابات متعددہ وارد کیے گئے تھے۔ اس قاعدے کلیے کو سورہ نساء میں مندرجہ ذیل کلمات کے ساتھ مشرح فرمایا گیا ہے:
ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدھم الموت قال انی تبت الاٰن ولا الذین یموتون وھم کفار اولئک اعتدنا لھم عذابا الیما۔ (سورہ النساء ۱۸)
(ترجمہ) ’’اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب سامنے آجاوے ان میں سے کسی کو موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔‘‘
جس نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ موت حاضر ہو جانے کے وقت میں (جب کہ علاماتِ موت ظاہر ہو جائیں اور انسان کو عالمِ غیب کی اشیاء دکھائی دینے لگیں) توبہ مقبول نہیں ہے، نہ عذابِ دنیوی دور ہوتا ہے اور نہ عذابِ آخرت سے رستگاری ہوتی ہے۔ نیز ان آیات نے صاف طور پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ فرعون، جس نے ادراکِ غرق اور عذابِ الٰہی کے مشاہدے کے بعد ایمان کے کلمات کہے، وہ ایماندار عند اللہ اور عند الشرح نہیں ہوا اور اس کی توبہ مقبول نہیں ہوئی۔ ادراکِ غرق کا مرتبہ تو رویتِ عذابِ الٰہی اور رویت یاسِ خداوندی سے بعد کا ہے، جب کہ رویت ہی سے ایمان کا نفع دینا ممنوع ہو جاتا ہے تو ادراکِ عذاب سے بدرجہ اولٰی ممنوع ہو گا۔
حضرت موسٰیؑ کا فرعون اور فرعونیوں کے لیے بد دعا میں ارشاد فرمانا ’’فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم‘‘ خود اس کے لیے شاہد عدل ہے۔ اگر ایسے وقت میں ایمان نافع ہوتا تو اس بددعا کے کوئی معنی نہیں تھے حالانکہ یہ دعا مقبول ہوئی اور فرمایا گیا ’’قد اجیبت دعوتکما‘‘ اور اسی بددعا کا بھی اثر تھا کہ فرعون نے مرتے وقت تک ایمان قبول نہ کیا۔ بہرحال ان آیات سے جو حکم اور قاعدۂ خداوندی مفہوم ہوتا ہے وہ نہایت قوی ہے اور ’’فصوص الحکم‘‘ میں جو استدلال ذکر کیا گیا ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی وقعت اور قوت نہیں رکھتا۔ غور فرمائیے۔ فرعون کے متعلق آیاتِ خصوصیہ بھی جمہور ہی کی تائید کرتی ہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا جاتا ہے:
ولقد ارسلنا موسٰی باٰیاتنا وسلطان مبین۔ الٰی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاردھم النار وبئس الورد المورود۔ واتبعوا فی ھذہ لعنۃ و یوم القیامۃ بئس الرفد المرفود۔ (سورہ ہود ۹۶۔۹۹)
(ترجمہ) ’’اور البتہ ہم بھیج چکے ہیں موسٰی کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے اور نہیں بات فرعون کی کچھ کام کی۔ آگے ہو گا اپنی قوم کے قیامت کے دن پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر، اور برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔ اور پیچھے ملتی رہی اس جہاں میں لعنت اور دن قیامت کے بھی، برا انعام ہے جو ان کو ملا۔‘‘
آیت مذکورہ بالا ’’یقدم قومہ الخ‘‘ کے جملے پر غور کریں، اگر اس کا ایمان عند اللہ معتبر ہوتا تو دوزخ کے وارد کرنے میں وہ سب سے آگے آگے کیوں ہوتا اور دنیا و آخرت میں لعنت کیوں اس پر کی جاتی؟ بالخصوص صاحبِ فصوصؒ کے اس قول کی بنا پر
فقبضہ طاھر او مطھر الیس فیہ شیئ من الحیف لانہ قبضہ عند ایمانہ قبل ان یکتسب شیئا من الاثام والاسلام یجب ما قبلہ۔
’’فرعون دنیا سے طاہر اور مطہر مرا، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں رہا، کیونکہ اس کی موت قبل اس کے کہ کچھ گناہ کرے ایمان کے ساتھ ہو گئی۔ اور اسلام ما قبل گناہوں کو محو اور قطع کر دیتا ہے۔‘‘
تو اس آیت کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے اور بالکل ہی مناقظہ لازم آتا ہے۔
نوٹ: یہ تاویل کرنا کہ ضمیریں صرف ملاء کی طرف راجع ہیں فرعون اس میں داخل نہیں ہے، خلافِ عربیت اور خلافِ لسانِ عربی ہے۔ بالخصوص جبکہ ’’یقدم‘‘ اور ’’قومہ‘‘ کی ضمیر خصوصیت کے ساتھ فرعون ہی کی طرف راجع ہوتی ہے اس لیے آئندہ کی ضمیری مجموعہ کی طرف ہی عائد ہوں گی۔
نیز یہ تاویل کہ وہ اپنی قوم کو تو داخل فی النار کرا دے گا مگر خود داخل نہیں ہو گا، بالکل غلط ہے۔ اگر اس کا امر بالمعصیت معصیت نہیں رہا تھا اور اسلام نے حسبِ ارشاد ’’یجب ما قبلہ‘‘ گزشتہ کو محو کر دیا تھا تو پھر یہ جزا ’’یقدم قومہ الخ‘‘ کیوں دی گئی اور وہ اگواکار کیوں بنایا گیا؟ اور جب کہ وہ طاہر اور مطہر ’’لیس فیہ شیئ من الحیف‘‘ ہے تو قیامت میں یہ معاملہ کیوں ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے تو ارشاد کیا گیا ہے ’’لا یسمعون حسیسھا‘‘ نیز دوزخ کی گرمی اور تغیظ زفیر شہیق وغیرہ مسیرۃ سبعین سنہ تک پہنچتی ہے، کیا اس ایراد قوم میں وہ خود عذاب میں مبتلا نہیں ہو گا؟ سورہ قصص میں ہے:
واستکبر ھو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انھم الینا لا یرجعون۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناھم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ وجعلناھم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون۔ واتبعناھم فی ھذہ الدنیا لعنۃ و یوم القیامۃ ھم من المقبوحین۔ (سورہ قصص۳۹۔۴۲)
’’اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں سو دیکھ لیا کیسا انجام ہوا گنہگاروں کا۔ اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی۔ اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے۔‘‘
ان آیات پر غور فرمائیے، اشک بار کی معصیت میں فرعون کی نسبت خاص طور پر ذکر کی گئی اور پھر مابعد کی ضمیریں مجموعہ کی طرف عائد کی جا رہی ہیں۔ نیز ’’ائمہ یدعون الی النار‘‘ کا حقیقی مصداق خود فرعون ہے، اس کے ملا کے لوگ تو ثانیاً و بالعرض ہوں گے اور ان سب کو قیامت میں مقبوح فرماتے ہیں۔ کیا ایمان اور اس کے اثار کے ہوتے ہوئے یہ جزائیں مترتب ہو سکتی ہیں؟ آیت:
فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق باٰل فرعون سوء العذاب۔ النار یعرضون علیھا غدوًا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا اٰل فرعون اشد العذاب۔ (سورہ مومن۴۵۔۴۶)
’’پھر بچا لیا موسٰیؑ کو اللہ نے برے داؤں سے جو وہ کرتے تھے اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہو گی قیامت حکم ہو گا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔‘‘
حضرت شیخؒ کی یہ تاویل کہ آلِ فرعون میں خود فرعون داخل نہیں ہے، قرآن کے محاورے کے خلاف ہے۔ فرمایا جاتا ہے ’’اعملوا اٰل داود شکرًا‘‘ (الآیۃ) میں بالاتفاق حضرت داؤدؑ مخاطب ہیں۔ اسی طرح آیت ’’ولقد اخذنا ال فرعون بالسنین‘‘ (الآیۃ) میں فرعون بھی بالاتفاق اس مواخذے میں داخل ہے۔ حضرت شیخ اکبرؒ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں، اس لیے یہ قول یا تو درحقیقت ان کا ہے ہی نہیں بلکہ ان کی تصانیف میں ملاحدہ نے چھپا کر داخل کر دیا ہے جیسا کہ امام العارفین شیخ عبد الوہاب شعرانیؒ اور دیگر اکابر کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر ان کا قول ہی ہو تو یقیناً اس میں ان سے خطا ہوئی ہے، وہ بڑے ہیں مگر معصوم نہیں ہیں، اس لیے جمہور کا قول صحیح ہے۔
حدیث قوی میں وارد ہے کہ اس کے اس قول کے وقت میں حضرت جبرائیلؑ نے دریا سے گارا نکال کر اس کے منہ میں بھر دیا کہ کہیں رحمتِ خداوندی اس کی نگرانِ کار نہ بن جائے ’’مخافۃ ان تدرکہ الرحمۃ‘‘ یہ فعل ان کا یقیناً بغض فی اللہ ہی کی بنا پر ہو سکتا ہے جو کہ اعلیٰ درجات ایمان میں سے ہے۔ مگر جو ہستی کہ ’’لا یعصون اللہ ما امرھم ویفعلون ما یؤمرون‘‘ کے مصادیق کی امام اور عند ذی عرش مکین مطاع اور امین ہو، بغیر مرضی خداوندی کب ایسا فعل اور عمل کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جملہ تاوییلات غیر مرضی اور غیر قابلِ التفات ہیں، قدرتِ خداوندی میں کلام نہیں، واقعات سے بحث ہے، واللہ اعلم۔ رحمتِ الٰہی کی وسعت اور نصوص سے معلوم ہوتی ہے اسی پر منحصر نہیں ہے۔
دُشمنانِ مصطفٰی ﷺ کے ناپاک منصوبے
اور خلقِ محمدیؐ کی اعجاز آفرینیاں
پروفیسر غلام رسول عدیم
سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ ہر دور کی مانی ہوئی حقیقت ہے۔ عرصۂ دہر میں جب بھی کوئی سچائی ابھری، ہر زمانے کے حق ناشناس لوگوں نے اس پر زبانِ طعن دراز کی بلکہ بسا اوقات مقابلے کی ٹھان لی۔ کیسے ممکن تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی صداقت کا ظہور ہو اور وہ بغیر کسی پس و پیش کے تسلیم کر لی جائے۔ یہ صداقت سرزمینِ عرب سے ابھری تو ایک زمانہ اس کے درپے آزار ہو گیا۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے حقیقتِ ابدی کو مہینوں نہیں سالوں لگے تاہم
؏ حقیقت خود منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی
تئیس سال میں یہ عظیم صداقت مانی گئی اور اس شان سے مانی گئی کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی
؏ فلک گفت احسن ملک گفت زہ
آفتابِ نبوت جلوۂ طراز ہوا تو اس کی جلوہ ریزیوں نے ایک عالم کو منور کر دیا مگر اس چمکتے اجالے میں بھی بعض شیرہ چشم اسلاف کی اندھی تقلید، ہوائے نفس اور سوسائٹی کی رسومِ باطلہ کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اس تیرگی میں بھٹک رہے تھے بلکہ وہ اس خورشیدِ جہاں تاب کو اپنی پھونکوں سے بجھانے پر اتر آئے تھے۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا معلوم تھا کہ
؏ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
یریدون لیطفؤوا نور اللہ بافواھھم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون (الصف ۸)
(وہ (کفار) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھا دیں (درآنحالیکہ) اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔)
سرورِ عالمؐ کی مکی زندگی کے تیرہ برس میں کفار و مشرکین نے انتہائی کوشش کی کہ وہ نخلِ اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکیں، جب آقائے دو جہاںؐ نے مدینے کو مستقر بنایا تو یہود و منافقین نے اپنی ناپاک سازشوں سے شجرِ اسلام کے استیصال میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ وہ بے بصر نہیں جانتے تھے کہ اس درخت کے مالی نے اسے ہر طرح کی آندھیوں اور طوفانوں سے محفوظ و مصون رکھنے کا عہد کر رکھا ہے
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحٰفظون۔ (الحجر ۹)
(ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔)
کج فکر معاندین اس نکتے کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب ایک عظیم الشان انسان کو مامور کیا جا رہا ہے تو کیا اس انسانِ کامل کو دشمنوں کے قبضے میں دے کر اس کی ماموریت کو معرضِ خطر میں ڈال دیا جائے گا۔ دشمنوں کا مامور من اللہ کو ہلاک کرنا اصل میں اللہ کی ماموریت کو کھلا چیلنج ہے، اس لیے آمر نے مامور کی حفاظت کی پوری پوری ذمہ داری کا اعلان فرما دیا
واللہ یعصمک من الناس۔ (المائدہ ۶۷)
(اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا)۔
اسی فکری نارسائی کی بنا پر کبھی ایسا ہوا کہ ایک شخص نے انفرادی سطح پر سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتمے کی کوشش کی جیسے مکی دور میں عقبہ بن ابی معیط نے حضورؐ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے بل دیا کہ گردن مبارک بھنچ گئی۔ قریب تھا کہ دم گھٹ جائے، اتنے میں صدیق اکبرؓ آ پہنچے، عقبہ کو دھکے دے کر الگ کیا اور یہ آیت پِڑھی:
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات (مومن ۲۸)
(کیا تم ایسے شخص کو مار ڈالتے ہو جو یہی تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے۔)
کبھی آپ کو گرفتار کر کے اعدائے اسلام کے قبضے میں دینے کی کوشش بھی کی گئی اور یہ گرفتاری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی جیسے سفرِ ہجرت میں سراقہ بن مالک بن جعشم نے تعاقب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ شعبِ ابی طالب میں تین سال کی محصوری پورے معاشرے کی طرف سے ہلاکتِ رسولؐ ہی کا ایک حربہ تھا۔ لیکن ان تخریبی سرگرمیوں اور اسلام دشمن کارروائیوں میں سب سے زیادہ گھناؤنے اور مکروہ جرم وہ تھے جو سرورِ کائنات کے قتل کے ناپاک منصوبوں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ ادھر دشمنانِ بداندیش قتل کے منصوبے سوچتے، سازشی میٹنگیں ہوتیں، قاتلانہ حملے کیے جاتے، ادھر شانِ رحمۃ للعالمین اور زیادہ نکھر کر سامنے آتی۔ خنجر بدست قاتل خلقِ محمدیؐ کے گھائل ہو کر لوٹتے۔ شکاری خود شکار ہوتے اور کارکنانِ قضا و قدر پکار اٹھتے
؏ لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا
پہلا منصوبہ
کتبِ سیرت میں یہ واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ ان سطور میں انہیں اجزائے پریشاں کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ ابھی کوئی چالیس مرد اور گیارہ عورتیں حلقہ بگوش اسلام ہوئی تھیں۔ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ ایک روز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی چیرہ دستیوں اور مسلمانوں کی کمزوری کے پیشِ نظر بارگاہِ ایزدی میں دعا کی
اللھم اید الاسلام بابی الحکم بن ھشام او بعمر بن الخطاب۔
دعا درِ اجابت تک پہنچی۔ ادھر عمر بن خطاب (جو اس وقت تک مسلمانوں کے سخت دشمن تھے) کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ عمر اس راز سے واقف نہ تھے، وہ تلوار لٹکائے ہوئے کوہِ صفا کے دامن میں دارِ ارقمؓ کی طرف اس ارادے سے چلے کہ آج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کا خاتمہ کرنے جاتا ہوں۔ راستے میں نعیمؓ بن عبد اللہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی درِپردہ مسلمان ہو چکے تھے، تیور دیکھ کر نیت کا فتور بھانپ گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے مدعا بیان کیا۔ نعیم بولے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کر بھی گزرے تو کیا بنی عبد مناف تمہیں یونہی زندہ چھوڑ دیں گے۔ دوسرے یہ کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ عمرؓ کے غیض و غضب کی انتہا نہ رہی، فورًا لوٹے، بہن کے گھر آئے، اندر سے تلاوتِ کلامِ الٰہی کی آواز سنائی دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے حضرت خباب بن الارتؓ کو الگ کر دیا، اوراق چھپا لیے۔ عمر نے آ کر پوچھا تو یہ طرح دے گئے، اس پر وہ بہنوئی پر پل پڑے، بہن بیچ میں آئیں تو ان کو بھی لہولہان کر دیا۔ پانی سر سے گزر گیا تو دونوں میاں بیوی نے کھل کر کہہ دیا
قد اسلمنا و اٰمنا باللہ ورسولہ فاصنع بذالک۔
’’ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر دیکھیئے۔‘‘
اب عمرؓ پسیجے، دل کی دنیا بدل چکی تھی، منصوبۂ قتل خاک میں مل گیا۔ قبولیت ِاسلام کا میلان دکھایا، آیاتِ الٰہی سننے کی فرمائش کی۔ بہن نے غسل کروا کر کپڑے بدلوائے، حضرت خباب بن الارتؓ بھی نکل آئے، اس سوز سے قرآن پڑھا کہ عمرؓ کی تقدیر پلٹ گئی۔ سورہ حدید تلاوت کی جا رہی تھی۔ ساتویں آیت پر ہی جب ’’امنوا باللہ ورسولہ‘‘ تک پہنچے تو عمر جنہیں فاروقِ اعظم بننا تھا بے اختیار پکار اٹھے
اشھد ان لا الٰہ الا اللہ واشھد ان محمدا رسول اللہ۔
تھوڑی ہی دیر بعد عمرؓ مرادِ رسولؐ بن کر سرِ تسلیم خم کیے دارِ ارقم ؓ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحابؓ کی معیت میں یہیں تشریف رکھتے تھے۔ حضراتِ حمزہؓ، ابوبکرؓ، علیؓ اور دیگر شائقینِ اولین خدمتِ اقدس میں حاضر تھے۔ شمشیر بدست قاتل پیغامِ نبوی (قرآن) کا گھائل ہو چکا تھا۔ کسی نے بند دروازے سے جھانک کر دیکھا، سہمے ہوئے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ! عمرؓ آ رہا ہے۔ حمزہؓ بولے، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو آنے دو ورنہ اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ یہ آن پہنچے۔ اجازت ملی، اندر آ گئے۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور سے چادر کھینچ کر آنے کا سبب دریافت فرمایا۔ سر نیہوڑائے ہوئے عمرؓ بولے
یا رسول اللہ جئتک لاؤمن باللہ و برسولہ و بما جاء من عند اللہ۔
’’یا رسول اللہ! اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔‘‘
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرۂ تکبیر بلند کیا، فضائے مکہ نعرہ ہائے تکبیر سے گونج اٹھی، کعبے میں اذان و نماز کا اہتمام ہوا۔
دوسرا منصوبہ
سرزمینِ مکہ تخمِ ایمان کی نشوونما کے لیے زرخیز ثابت نہ ہوئی۔ وہ شاخِ ہاشمی جسے ایک روز برگ و بر پیدا کرنے تھے مکہ مکرمہ کی ناخوشگوار فضا میں پنپ نہ سکی تو ؎
عقیدۂ قومیت مسلم کشود
ازوطن آقائےؐ ہجرت نمود
نبوت کے تیرہویں سال اکثر مسلمان راہِ خدا میں اپنے گھر کو خیرباد کہہ کر کوئی پونے تین سو میل دور یثرب میں جا مقیم ہوئے تھے۔ قریش محسوس کر رہے تھے کہ ایک دن رسالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکہ چھوڑ دیں گے۔ اس خطرے کے پیشِ نظر مکہ کے پبلک ہال دارالندوہ میں ایک خصوصی اور ہنگامی اجلاس ہوا جس میں ایک بہت بڑی سازش کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس میٹنگ میں ایک دو نہیں مکے کی غیر مسلم اکثریت کے سارے ہی نمائندے شریک تھے۔ دوسروں کے علاوہ قریش کے سات قبیلوں کے چودہ سربرآوردہ لیڈر پیش پیش تھے۔ ان کی تفصیل یوں ہے:
(۱) بنو نوفل سے طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، اور حوث بن عامر بن نوفل
(۲) بنو عبد الشمس سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ابو سفیان بن حرب
(۳) بنو عبد الدار بن قصی سے نفر بن حارث بن کلدہ
(۴) بنو اسد بن عبد العزٰی سے ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود بن عبد المطلب، اور حکیم بن حزام
(۵) بنو مخزوم سے ابوجہل بن ہشام
(۶) بنو سہم سے منیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج
(۷) بنو حمح سے امیہ بن خلف
بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانے لگیں، طرح طرح کی تجویزیں زیرغور آئیں، ایک بولا اسے زنجیروں میں جکڑ کر محبوس کر دیا جائے۔ اس پر ایک شیخ صورت ابلیس نے کہا بنی عبد مناف اور پیروانِ اسلام اسے چھڑا لیں گے۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اسے جلا وطن کر دیا جائے، پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ اس پر پھر بڈھا ابلیس بولا، اس کی شیرینی بیان سے تو تم سب واقف ہو، جلاوطنی سے وہ پورے عرب میں معروف و مقبول ہو جائے گا۔ آخر الامر مخزومی گرگ باراں دیدہ ابوجہل بن ہشام کی یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور ہوئی کہ تمام قبائل میں سے چند تجربہ کار تیغ زن چن لیے جائیں اور وہ یکبارگی محمدؐ پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح بنو عبد مناف کو کسی ایک فرد یا قبیلے کی بجائے تمام قبائل سے ٹکر لینا پڑے گی، وہ ان سے لڑنا تو کیا دیت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکیں گے، ان میں ان سے نپٹنے کی ہمت ہی نہیں، ان کے پیروکار بھی سب کو موردِ انتقام نہیں بنا سکیں گے۔
اللہ اللہ دارالندوہ میں یہ سازش کی جا رہی ہے اور رب ذوالجلال اس سازش کی ناکامی کا بھرپور اعلان فرما رہے ہیں:
واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، ویمکرون ویمکر اللہ، واللہ خیر الماکرین (الانفال ۳۰)
(اور کفار جب آپؐ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر ڈالیں، وہ داؤ پر تھے اللہ ان کے داؤ کو غلط کر رہا تھا، اور اللہ چالوں کو سب سے بہتر ناکام بنانے والا ہے۔)
ادھر اس منڈلی نے یہ تجویز پاس کی، ادھر سرور عالمؐ نے باشارۂ وحیٔ الٰہی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکرؓ کو ان کی درخواست پر شرفِ معیت بخشنے کے لیے پہلے ہی مطلع فرما دیا۔ عم زاد حضرت علیؓ سے ارشاد فرمایا، آج میری خضری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہنا اور صبح کے وقت یہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے مدینے چلے آنا۔
جب رات کی تاریکی چھائی تو معاندینِ مکہ کی شمشیرباز ٹولی مجوزہ پروگرام کے تحت اپنی ڈیوٹی پر آن حاضر ہوئی۔ خانۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاضرہ کر لیا۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی رات گزرنے پر سورہ یس کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے۔ محاصرین پر گویا مدہوشی طاری ہو گئی، حضورؐ آیت پر پہنچے تو زبانِ مبارک سے یہ الفاظ نکلے:
وجعلنا من بین ایدیھم سدًا ومن خلفھم سدًا فاغشینھم فھم لا یبصرون (یس ۹)
(ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا)
ایک مٹھی خاک محاصرین کے سروں پر پھینکی اور باہر نکل آئے۔ حضرت ابوبکرؓ کے گھر پہنچے جو پہلے سے چشم براہ تھے، یہاں سے شہر مکہ سے جنوبی جانب غارِ ثور میں پہنچ گئے۔ یہ ناپاک منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، خدائے عزوجل نے اپنے محبوب کی محافظت کا خود بندوبست فرما دیا تھا۔
تیسرا منصوبہ
۱۷ رمضان المبارک ۲ھ کو میدانِ بدر میں کفر و اسلام کا پہلا معرکۂ کارزار گرم ہوا۔ مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی۔ قریش خائب و خاسر لوٹے۔ ان کے دل و دماغ میں شکست خوردگی کے بعد بغض وعناد کا الاؤ جل رہا تھا۔ کہاں غلامانِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنا اور کہاں یہ ذلت آمیز ەزیمت
؏ہر شخص جل رہا تھا عداوت کی آگ میں
عمیر بن وہب اور صفوان بن اُمیہ بھی انہی معاندین اور آتشِ زیرپا لوگوں میں سے تھے جن کے لواحقین یا تو میدانِ بدر میں کام آئے یا بحالتِ اسیری تھے۔ دونوں بدر کے اگلے روز مکہ سے باہر ایک ویران جگہ میں ملے۔ صفوان کا باپ امیہ مقتولین بدر میں سے تھا اور عمیر کا بیٹا وہب مدینے میں بنی زریق کے رفاعہ بن رافع کا قیدی تھا۔ آتشِ غضب و عداوت میں جلتا ہوا عمیر بولا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے اہل و عیال سے فراغت ہوتی تو میں مدینے جا کر محمدؐ کا کا سر قلم کر دیتا۔ صفوان جو قتلِ پدر کا زخم کھائے ہوئے پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، جھٹ بول اٹھا، میں تیرا قرض چکا دوں گا اور تاحیات تیرے بال بچوں کی کفالت کروں گا، تو یہ کام کر گزر۔ دونوں یہ باتیں مکمل تنہائی میں کر رہے تھے، چنانچہ رازداری کا عہد و پیمان ہوا۔ عمیر نے اپنی تلوار تیز کی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مدینے کی راہ لی۔
مدینے پہنچا تو مسجد نبویؐ کے سامنے اونٹ بٹھایا۔ ادھر حضرت عمرؓ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ فتح بدر کے بارے میں فضلِ خداوندی پر بات چیت کر رہے تھے۔ اونٹ کے بلبلانے سے عمیر کو دیکھا، دیکھتے ہی سمجھے کہ یہ شیطان بے سبب نہیں آیا، ضرور اس کی نیت میں فتور ہے۔ اس کی تلوار کے قبضے کو سنبھال گردن سے پکڑ کر بارگاہِ نبوت میں پہنچے۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے آنے کا سبب دریافت فرمایا۔ بولا، اپنے بیٹے وہب بن عمیر کی رہائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر استفسار فرمایا، آمد کی اصل وجہ کیا ہے؟ پھر وہ ٹال گیا۔ اس پر بصیرتِ نبویؐ کا اعجاز رنگ لایا۔ فرمایا، کیا تم اور صفوان بن امیہ سنسان جگہ میں بیٹھے قریش کے اصحاب القلیب کی باتیں نہیں کر رہے تھے؟ پھر تو نے صفوان بن امیہ سے نہیں کہا تھا کہ اگر مجھ پر قرض کا بار نہ ہوتا اور اہل و عیال کا بار نہ ہوتا تو میں محمدؐ کو قتل کر دیتا اور اس نے ذمہ اٹھا لیا تھا۔ عمیر بول اٹھا ’’اشھد انک رسول اللہ‘‘ یا رسول اللہ ہم آپ کی سماوی خبروں کی تکذیب کیا کرتے تھے مگر یہ بات تو میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو معلوم نہ تھی، ’’فالحمد للذی ھدانی للاسلام‘‘۔
چوتھا منصوبہ
کعب بن اشرف یہودی جو مدینے میں سرورِ عالمؐ کا بدترین دشمن تھا، یہودیت کا پرجوش حامی و مبلغ تھا، بڑا قادر الکلام شاعر تھا، بدر میں مشرکین مکہ کی عبرت ناک شکست کے بعد مکے جا کر مقتولین بدر کے مرثیے پڑھ پڑھ کر مرد و زن کو رلاتا اور آمادۂ انتقام کرتا۔ واپس مدینے آیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دریدہ دہنی کو اپنا شعار بنا لیا۔ نابکار جگہ جگہ ہجوِ رسولؐ کرتا۔ اس کے دل میں اس قدر بغض و عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے قصد کیا کہ چپکے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دے مگر قرآن کے اس فیصلے ’’ولا یحیق المکر السیئ الا باھلہ‘‘ (بری چال چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہے) کے مصداق خود ہی محمد بن مسلمہؓ کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا۔
پانچواں منصوبہ
حادثہ فاجقہ بئرمعونہ (صفر ۴ھ) کے بعد حضرت عمرو بن امیہؓ الضمری جب مدینے کی راہ میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، قبیلۂ بنی عامر کے دو شخص اسی درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گئے۔ عمرو بن امیہؓ شہدائے بئرمعونہ کے غم سے نڈھال بھی تھے اور بنی عامر کی قساوت پر غصے سے بھرے ہوئے بھی۔ انہوں نے ان دونوں کو دشمن جان کر موت گھاٹ اتار دیا حالانکہ حضورؐ ان دونوں کو جان کی امان دے چکے تھے۔ جب اس واقعہ کی اطلاع سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو بئر معونہ میں اس قبیلے کے مظالم کے باوجود فرمایا ان کی دیت مجھے ادا کرنا ہو گی۔ قبیلۂ بنی عامر یہود کے قبیلۂ بن نضیر کا حلیف تھا۔ چنانچہ سرور عالمؐ یہود کے قبیلہ بنی نظیر میں اس غرض سے تشریف لے گئے کہ ان سے قبیلہ بنی عامر کے خون بہا کے بارے میں استفسار فرمائیں کہ ان کے ہاں دیت کا دستور ہے۔ حضورؐ کی تشریف آوری پر بنی نضیر نے اس سلسلے میں بظاہر مثبت رویے کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح حضورؐ چاہیں اسی طریقے سے دیت ادا کر دیں۔
پھر یہ نابکار الگ ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس سے اچھا موقع کیا ملے گا؟ حضورؐ دیوار کے قریب ہیں، کوئی دیوار پر چڑھ کر پتھر لڑھکا دے۔ بدبخت عمرو بن حجاش بن کعب نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا۔ وہ کوٹھے پر چڑھا ہی تھا کہ سرورعالمؐ نے فراستِ نبوی اور اطلاع غیبی سے معلوم کر لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپؐ اس جگہ سے فی الفور ہٹ گئے، اٹھے اور واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس سفر میں حضرات ابوبکرؓ، عمرؓ اور علیؓ بھی شرف ہمسفری سے مشرف تھے۔ کعب بن اشرف کے ناپاک منصوبے کے بعد قتلِ رسولؐ کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا۔
چھٹا منصوبہ
مشرکین مکہ غزوۂ احزاب ۵ھ تک اپنے کس بل دکھاتے رہے مگر اس جنگ نے ان کی سیاسی طاقت قریب قریب ختم کر دی۔ مگر اب مدینے کے یہودی اور منافق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ کعب بن اشرف کے انفرادی اور بنی نضیر کے اجتماعی منصوبۂ قتل کے بعد یہود نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ۷ھ میں خیبر فتح ہوا۔ حضورؐ ابھی خیبر ہی میں تشریف رکھتے تھے کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت الحرث نے پورے فتورِ نیت سے حضورؐ کی دعوت کی، بکری کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ملا دیا۔ یہ تک معلوم کر لیا کہ حضورؐ بکری کے گوشت کا کونسا حصہ زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس حصے کو زیادہ مسموم کر دیا۔ جب حضورؐ نے کھانا تناول فرمانے کے لیے دستِ مبارک بڑھایا تو اعجازِ نبوت کی اثر آفرینی سے گوشت کے زہریلا ہونے کا راز آپؐ پر منکشف ہو گیا، فی الفور کھانے سے دست کش ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ تھوڑا سا چکھا بھی تھا۔
ایک صحابی بشیر بن برا بن المعرور نے ایک لقمہ کھا لیا، کھانے سے فورًا ہاتھ اس لیے نہ کھینچا کہ حضورؐ کے سامنے سوء ادبی ہو گی، وہ موقع پر یا بروایت ایک سال بعد انتقال کر گئے۔ بعد میں حضورؐ نے اس عورت کو بلایا، پوچھنے پر عورت نے گوشت مسموم کرنے کا اقرار کر لیا۔ اس سازش کے اصل مجرموں سے، جو پس منظر میں رہے تھے، پوچھ گچھ کی گئی تو وہ بھی اس ارادۂ قتل کے معترف ہو گئے مگر ایک اچھا سا بہانہ تراش لیا کہ ہم نے ایسا بغرضِ امتحان کیا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے یہ یہود کا خبثِ باطن اور عذرِ گناہ بد تر اَز گناہ تھا۔
ساتواں منصوبہ
سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک درخت کے سائے میں استراحت فرما رہے تھے، تلوار ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دی تھی، غوث بن الحرت آیا اور چپکے سے تلوار سنبھال لی، بڑی گستاخی سے سرورِ عالمؐ کو بیدار کر کے کہا، اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ آپؐ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، اللہ! وہ رعبِ نبویؐ سے سہم کر گرا۔ حضورؐ نے تلوار سنبھال لی اور یہی سوال اس سے کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، لرزنے لگا، آپؐ نے فرمایا، جاؤ میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔
آٹھواں منصوبہ
ہجرت کا آٹھواں سال تھا مکہ فتح ہو گیا ’’جاء الحق و زھق الباطل ان الباطل کان زھوقا‘‘ (الاسراء ۸۱)۔ فضائے مکہ نعرہ ہائے تکبیر سے گونج رہی تھی، ۳۶۰ بت منہ کے بل گر کر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ فتح مکہ سے اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروفِ طواف تھے، ایک بداندیش فضالہ بن عمیر نے موقع دیکھ کر قتل کا منصوبہ بنایا۔ شاید اس وقت آپ اکیلے تھے، پوری طمانیت سے طواف فرما رہے تھے۔ فضالہ فتور بھری نیت سے قریب آیا، زبانِ نبوت سے نکلا فضالہ آتا ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے؟ فضالہ بولا، ذکر الٰہی کر رہا ہوں۔ ملہم بالغیبؐ کے حسین چہرے پر تبسم کی کلیاں مہکیں اور یوں گویا ہوئے، اپنے لیے خدا سے معافی مانگو۔ اور ساتھ ہی اس جانِ رحمت نے اپنا دست مبارک فضالہ کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر سکون و طمانیت ملی اور دل میں حضورؐ کی محبت اس درجہ موجزن ہوئی کہ آپؐ سے بڑھ کر میری نگاہوں میں کوئی چیز محبوب نہ رہی۔
اگلے ہی لمحے وہ دشمنِ جان عاشقِ زار رسولؐ بن کر حلقۂ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ طواف سے فارغ ہو کر گھر کو چلا تو راہ میں اس کی معشوقہ ملی، پکاری، فضالہ! بات تو سنو۔ فضالہ نے سنی اَن سنی کرتے ہوئے جواب دیا، خدا اور اس کا رسول ایسی باتوں سے منع فرماتے ہیں۔
نواں منصوبہ
۹ھ میں جنگِ تبوک سے واپس ہو رہے تھے کہ منافقین نے قتلِ رسولؐ کا منصوبہ بنایا۔ تبوک سے واپسی پر یہ ٹولی آپس میں بڑی زہرناک گفتگو کر رہی تھی۔ باہمی مشورے سے طے یہ کیا گیا کہ جب رات کی تاریکی میں مسلمان پہاڑ سے گزر رہے ہوں تو حضورؐ کو عقبہ سے نیچے گرا کر ہلاک کر دیا جائے۔ بدبخت جلاس بن سوید نے کہا، آج رات ہم محمدؐ کو عقبہ سے گرائے بغیر نہ رہیں گے، چاہے محمدؐ اور ان کے ساتھی ہم سے بہتر ہی ہوں، مگر ہم لوگ بکریاں ہیں اور یہ ہمارے چرواہے بن گئے ہیں، گویا ہم بے عقل ہیں اور یہ سیانے۔ اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان میں حصن بن نمیر وہ شخص تھا جو صدقے تک کی کھجوریں لوٹ لے گیا تھا اور چور بھی تھا۔ منافق طعیمہ بن ابیرق نے کہا، آج کی رات جاگو تو سلامت رہو گے، تمہارا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ مرّہ نے کہا، بس ہم اگر اس ایک شخص کو قتل کر دیں تو سب کو اطمینان ہو جائے گا۔
یہ منافق تعداد میں کل بارہ تھے۔ اہلِ سیر نے ان کے نام گنوائے ہیں۔ ابو عامر جو راہب کہلاتا تھا اور حضرت حنظلہؓ (غسیل الملائکہ) کا باپ تھا، ان کا سردار تھا۔ (۱) عبد اللہ بن ابی (۲) سعد بن ابی سرح (۳) ابا خاطر الاعرابی (۴) عامر (۵) ابو عامر راہب (۶) جلاس بن سوید (۷) مجمع بن جاریہ (۸) ملیح الیتمی (۹) حصن بن نمیر (۱۰) طعیمہ بن ابیرق (۱۱) عبد اللہ بن عیینہ (۱۲) مرہ بن ربیع۔
منصوبۂ قتل یوں تھا کہ جب وہ سازش کر رہے تھے، سرِشام ہی سرورِ عالمؐ نے اشارۂ غیبی اور فراستِ نبویؐ سے ان کی بدنیتی کو بھانپ لیا۔ ارشاد فرمایا، جو کوئی وادی کے کشادہ راستے سے گزرنا چاہے ادھر چلا جائے، مگر خود گھاٹی (عقبہ) سے گزرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت حذیفہؓ بن یمان ناقہ کو ہانک رہے تھے اور عمار بن یاسرؓ ناقۂ رسولؐ کی نکیل تھامے چل رہے تھے۔ رات تاریک ہو گئی تو یہ بارہ منافق نقاب پوش ہو کر حملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ پا کر حذیفہؓ سے ارشاد فرمایا کہ انہیں آگے آنے سے روکیں۔ حذیفہؓ نے مڑ کر ایک شخص کے اونٹ کی تھوتھنی پر ترکش مارا۔ وہ سمجھے کہ راز فاش ہو گیا۔ جلدی سے مڑے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ کو تیز ہانکنے کا حکم دیا۔ عقبہ سے سلامت گزر گئے۔ حذیفہؓ سے ان کے نام بیان فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے مگر عالمِ الغیب نے بروقت مجھے خبردار کر دیا۔
سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو ایک ایک منافق کو بلا کر اس سے استفسار فرمایا، کسی نے معذرت کی، کوئی شرم سے گڑ گیا، بعض مرتد ہو گئے۔ خالقِ کائنات نے انہی کی بابت قرآن کریم میں بدیں الفاظ تبصرہ فرمایا ’’وھمّوا بما لم ینالوا‘‘ (التوبہ ۷۴)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپؐ ہر قبیلے کو حکم دیں کہ وہ اپنے منافق کا سر کاٹ کر حضورؐ کی خدمت میں پیش کرے مگر شانِ رحمت للعالمینی آڑے۔ فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ عربوں میں یہ چرچا ہو کہ محمدؐ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے دشمنوں پر غلبہ پایا پھر ان ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس شانِ کرم، جانِ عفو اور سراپائے حلم نے ان خون کے پیاسوں کو معاف فرما دیا۔ جان کے بیریوں کو محبتِ فاتحِ عالم نے اپنا بنایا۔ عناد بھرے سینوں کو شفقت و رأفت سے معمور کر دیا۔
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ سیدنا محمد واٰلہ وصحبہ و بارک وسلم۔
آزاد جموں و کشمیر ۔ پاکستان میں نفاذِ اسلام کے قافلے کا ہراول دستہ
ادارہ
آج سے ۴۲ سال قبل جب ہندوستان کی تقسیم کے فارمولے پر دستخط کیے گئے تو یہ ضابطہ بھی متفقہ طور پر طے کیا گیا کہ وہ ریاستیں جو انگریز کی عملداری میں شامل نہیں اور جن پر مستقل طور پر راجے اور دیگر حکمران حکمرانی کر رہے ہیں، ان میں جس ریاست میں ہندو اکثریت میں ہوں مگر حاکم مسلمان ہوں وہ ہندوستان میں شامل ہوں گی، اور جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں اور حاکم ہندو ہو وہ پاکستان میں شامل ہوں گی۔ ہندوستان نے اپنی روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس اصول کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیر دیں اور یوں مناور، جوناگڑھ، حیدرآباد، گوا اور کشمیر پر قبضہ جما لیا۔
اکتوبر ۱۹۴۷ء میں جب وادیٔ کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کی عیاری اور ہندوستان کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف کشمیر مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے اور قبائلی مسلمانوں نے ان کی مدد کے لیے وادی پر یلغار کی تو ہندوستان کی بزدل افواج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مجاہدین سری نگر کے ہوائی اڈے تک پہنچ گئے اور یہ حسین وادی آزادی سے چند قدم دور رہ گئی کہ بعض ناعاقبت اندیش لیڈروں نے ہندوستان کی چیخ و پکار پر جنگ بندی قبول کر لی اور اقوام متحدہ کے دامِ فریب میں آ کر نام نہاد رائے شماری کی قرارداد کو قبول کر لیا گیا۔ یوں ایک کروڑ بیس لاکھ مسلمانوں کو پھر سے غلامی کی زنجیروں میں دھکیل دیا گیا، تاہم وادی کا ایک حصہ جسے ایک تہائی حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، ہندوستان کے پنجۂ استبداد سے آزاد کرا لیا گیا، اس آزاد حصے کو آج کل ’’آزاد جموں و کشمیر‘‘ کہا جاتا ہے۔
وادیٔ کشمیر کے لوگوں کو اسلام سے گہری محبت ہے اور بیشتر لوگ اسلامی احکام کے پابند ہیں۔ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۷۲ء تک مختلف حکومتیں آزاد کشمیر میں برسرِ اقتدار رہیں اور اپنی اپنی بساط کے مطابق کسی حد تک ریاست کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی مگر پاکستان کی وزارت اور کشمیر کے بزرجمہروں نے ان کی ایک نہ چلنے دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح طریقہ سے اسلامی قوانین کی تنفیذ ناممکن ہو گئی۔
مجاہدِ اول سردار محمد عبد القیوم خان کا دورِ حکومت
۱۹۷۲ء میں سردار محمد عبد القیوم خان ایک منتخب حکمران کی حیثیت سے آزادکشمیر کی صدارت پر متمکن ہوئے اور اپنی جرأتمندانہ قیادت کے نتیجے میں وزارتِ امورِ کشمیر کی بالادستی سے نجات حاصل کی اور فوری طور پر ریاست کو صحیح اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے نظامِ افتاء کو ازسرِنو زندہ کیا جسے سابقہ حکومت نے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ تمام تحصیلوں اور اضلاع میں تحصیل مفتی اور ضلع مفتی مقرر کیے گئے۔ جیلوں میں مفتیوں کی اسامیاں تخلیق کی گئیں اور یوں اسلامی نظام کی طرف پیشرفت کا آغاز ہوا۔
نظامِ قضا کا قیام
۱۹۷۵ء میں ایک قانون کے ذریعے پوری ریاست میں اسلامی حدود نافذ کر دی گئیں اور چوری، زنا، ڈکیتی، قذف، شراب نوشی، قتل کے جرائم کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ چونکہ پہلے سے جاری نظامِ عدالت انگریزی قوانین کے سند یافتہ ججوں پر مشتمل تھا اس لیے شرعی حدود کے نفاذ کے بعد ان حضرات کے لیے فیصلے کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ علماء کرام کو ان کے اصلی کام یعنی منصبِ قضا پر فائز کیا گیا اور ہر فوجداری عدالت میں سب جج (تحصیل قاضی) اور سیشن جج (ضلع قاضی) دو افراد پر مشتمل بینچ قائم کر دیے گئے۔ جہاں دینی علوم کے ماہر علماء کرام اور انگریزی قانون کے ماہر جج صاحبان مل کر انتہائی محبت، خلوص اور برابری کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور کبھی بھی ججوں اور قاضیوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ کسی احساسِ برتری یا کمتری کی بنیاد پر نہیں ہوا۔
قتلِ مرتد
اس سلسلہ میں بھی حکومتِ آزاد کشمیر نے اپنے اختیارات کی حد تک بے حد کوشش کی مگر اس وقت پاکستان میں برسرِ اقتدار گروپ نے قانونِ ارتداد نہ نافذ ہونے دیا۔ اور قارئین کو یاد ہو گا کہ آزادکشمیر اسمبلی نے ۱۹۷۴ء میں قادیانیوں کے خلاف جو قرارداد منظور کی تھی اس پر پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں کا کیا ردعمل تھا اور کس طرح آزادکشمیر کے منتخب صدر کی رہائشگاہ کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا، اس تمام دباؤ کے باوجود اس وقت ’’مسلم کانفرنس‘‘ کی حکومت نے اسلامی قوانین نافذ کیے۔
دوسرا مرحلہ
آزادکشمیر کی منتخب حکومت بنوکِ شمشیر برطرف کر دی گئی اور یوں ۱۹۷۵ء کے اواخر سے لے کر ۱۹۸۵ء تک مختلف نامزد حکمران آزاد کشمیر پر حکمران رہے۔ مگر خدا کے فضل و کرم سے اسلامی قوانین جوں کے توں نافذ رہے اور کسی گروہ کو ان قوانین کے معطل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
۱۹۸۳ء کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جب پھر مسلم کانفرنس بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور سردار سکندر حیات کی سرکردگی میں حکومت تشکیل دی گئی۔ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صدر منتخب ہوئے۔ مسلم کانفرنس حکومت کے اولین مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ جو کام ۱۹۷۵ء میں رہ گیا تھا اسے موجودہ چہار سالہ مکمل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس چہار سالہ میں مزید اسلامی اقدامات کیے گئے۔ مڈل اور ہائی اسکولوں میں قراء کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر اسمبلی نے ۱۹۸۹ء کے سیشن میں متفقہ طور پر شریعت بل پاس کیا جس کے نتیجے میں ریاست کی تمام عدالتوں کو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند کر دیا گیا۔ عوام الناس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کسی بھی فیصلہ یا قانون کو خلافِ شریعت قرار دینے کے لیے شریعت کورٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
شعبۂ افتاء کا قیام
نظامِ قضا اور افتاء کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے قضاۃ کو عدلیہ کے تابع کر دیا گیا اور محکمہ امور دینیہ کے زیرانتظام شعبۂ افتاء کا قیام عمل میں لایا گیا۔ شعبۂ افتاء کا قیام ریاستی مسلمانوں کی اہم ضرورت تھی جس کے لیے حکومت نے اٹھارہ لاکھ روپے کی خطیر رقم منظور کی، اور ہر ضلع میں گریڈ ۱۸ کا ایک ضلع مفتی مقرر کیا گیا اور ہر تحصیل میں گریڈ ۱۷ کا تحصیل مفتی مقرر کیا گیا۔ اس طرح آزادکشمیر کی سولہ تحصیلوں میں سولہ علماء دین بطور تحصیل مفتی مقرر کیے گئے اور پانچ اضلاع میں پانچ علماء دین بطور ضلع مفتی مقرر کیے گئے۔
انتخاب
مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان چونکہ بذات خود محکمہ افتاء کے قیام میں دلچسپی لے رہے تھے اس لیے انہوں نے مفتیوں کے انتخاب میں بھی بلند معیار کو ملحوظ رکھا۔ انہوں نے خود اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ارکان میں مولانا محمد یوسف (شیخ الحدیث دارالعلوم پلندری) اور مولانا سید مظفر حسین شاہ ندوی جیسے متبحر علماء دین شامل تھے۔ چنانچہ اس انتخابی کمیٹی نے تقریباً دو سو علماء میں سے ۱۶ کو بطور تحصیل مفتی منتخب کیا اور ضلع مفتی کے انتخاب کے لیے مصروف اور تجربہ کار علماء جو تعلیمی اعتبار سے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے ان کو ضلع مفتی کے منصب کی پیشکش کی گئی۔ تحصیل مفتی صاحبان میں بعض حضرات نہ صرف درسِ نظامی کے فارغ التحصیل ہیں بلکہ مروجہ طریقۂ تعلیم میں ایم اے بھی ہیں۔ ضلع مفتی صاحبان میں اکثریت درسِ نظامی کے فارغ التحصیل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایم اے، ایل ایل بی اور عرصۂ دراز تک منصبِ افتاء پر فائز رہنے والے علماء بھی ہیں، اور بعض غیر ملکی یونیورسٹیوں سے ایل ایل بی، ایل ایل ایم کی اسناد کے حامل ہیں۔
اس طرح اس دفعہ اس نئے اور تجدیدی شعبہ کے لیے نہایت قابل افراد کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں راقم کی رائے میں اگر شعبہ قضاء میں منتقل کر کے ان کی خدمات شریعت کورٹ کے سپرد کر دی جائیں تو وہ ہائیکورٹ، شریعت کورٹ، سپریم کورٹ میں زیادہ بہتر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔
مفتیانِ کرام کے فرائض
حکومتِ آزاد کشمیر کی اسلامائزیشن کی پالیسی کے سلسلہ میں شعبۂ افتاء کے قیام کا اصل مقصد ریاست میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ سینئر مفتی حضرات کے مزید فرائض حسبِ ذیل ہوں گے:
(۱) دعوت و ارشاد، لوگوں میں تبلیغ دین، مجالس دینیہ کا انعقاد، محافلِ سیرت، مقابلہ ہائے حسنِ قراءت کا انعقاد، اتحادِ علماء اور باہمی اخوت یگانگت کا فروغ۔
(۲) ریاست میں نکاحوں کا سلسلہ خطرناک حد تک فتنہ و فساد کا باعث بن گیا تھا اور جھوٹے دعوؤں سے عدالتیں اٹ گئی تھیں۔ چنانچہ اس سلسلہ کو روکنے کے لیے حکومت نے نکاحوں کی رجسٹریشن کا قانون نافذ کیا۔ مفتی صاحبان کو رجسٹرار مقرر کیا گیا ہے جسے مجل (ضلع مفتی)، نائب مجل (تحصیل مفتی) کہا جائے گا۔
(۳) رمضان المبارک میں سرِ عام کھانے پینے پر پابندی کا ایکٹ ریاست میں پہلے ہی نافذ ہے۔ اس پر عملدرآمد کے اختیارات مفتیانِ کرام کو دیے گئے ہیں اور مسودۂ قانونی حکومت کے زیرغور ہے۔
(۴) احکامِ جمعہ پر عملدرآمد کے اختیارات بھی مفتی صاحبان کو دیے گئے ہیں۔
(۵) حکومتِ آزاد کشمیر نے ۱۹۷۲ء سے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہفتہ وار درسِ قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پہلے درسِ قرآن پاک جمعرات کو ہوتا تھا، اب ہر سوموار کو دس سے گیارہ بجے تک تمام سرکاری ملازمین کی درس میں حاضری لازمی قرار دی گئی ہے۔ اور سیکرٹریٹ/ہائیکورٹ، ضلعی عدالتوں، تحصیلوں اور بڑے بڑے اداروں میں مفتی صاحبان اور مقامی علماء کرام درس دیتے ہیں۔ اس طرح ریاست کا اسلامی تشخص روز بروز اجاگر ہو رہا ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔
دینی مدارس کی تنظیم
آزاد کشمیر میں سینکڑوں دینی مدارس کام کر رہے ہیں جن کی تنظیم و ربطِ باہمی کا کام بھی مفتی صاحبان کے سپرد کیا گیا ہے اور ان مدارس کی رجسٹریشن اور سرکاری امداد کے لیے سفارشات بھی مفتی صاحبان کی ذمہ داری ہو گی۔
غرضیکہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت جناب مجاہد اول سردار عبد القیوم خان اور سردار سکندر حیات کی سربراہی میں اپنی بساط کے مطابق اَن تھک کام کر رہی ہے۔ اور اسی اسلامائزیشن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر کا مسلمان اس تعمیر و ترقی کو دیکھ کر ہندوستان کے غاصب حکمرانوں کے خلاف میدانِ کارزار میں نکل پڑا ہے اور اب وادیٔ کشمیر آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے۔ مگر ہندو بنیئے کی گولیاں آزادی کے جذبے کو سرد نہیں کر سکتیں۔ خدا وہ دن جلد لائے جب وادیٔ کشمیر پر لا الٰہ الا اللہ کا پرچم لہرائے اور پوری وادی اسلامی قوانین کی برکات سے مالامال ہو۔ خدا پاکستان کے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس چھوٹی سی ریاست کی پیروی کریں۔
ایسٹر ۔ قدیم بت پرستی کا ایک جدید نشان
محمد اسلم رانا
عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیحؑ تیسرے دن مُردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ عیسائی اس واقعہ کی یاد میں جو تہوار مناتے ہیں اسے ایسٹر کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسٹر کو عیدِ قیامت مسیحؑ یا عید پاشکا بھی کہتے ہیں۔ عیسائیت کی تاریخ میں یہ سالانہ منایا جانے والا پہلا اور قدیم ترین تہوار ہے۔ رومن کاتھولک جریدہ رقمطراز ہے:
’’قیامت مسیحؑ کی عید کو انگریزی میں ایسٹر کہتے ہیں۔ انگریزوں کے مسیحی ہونے سے پہلے وہ لوگ موسمِ بہار کی دیوی مانتے تھے اور اس دیوی کا نام ایسٹر تھا۔ مسیحیوں نے اس دیوی کو بھلا دینے کے لیے موسمِ بہار میں آنے والی مسیحی عید کا نام ایسٹر رکھ دیا اور یوں لفظ ایسٹر کے نام تبدیل ہو گئے۔ موسمِ خزاں یا پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ مُردہ سےمعلوم ہوتے ہیں، لیکن موسمِ بہار میں نئے پتے نکل آتے ہیں گویا درختوں میں پھر زندگی آجاتی ہے۔ اس مشابہت کی بنا پر مسیحؑ کے پھر زندہ ہونے کی عید کو ایسٹر کہنے لگے۔ یہ عید ۲۵ مارچ سے ۲۵ اپریل تک کسی اتوار کو منائی جاتی ہے۔‘‘ (پندرہ روزہ کاتھولک نقیب لاہور ایسٹر نمبر ۱۹۸۶ء)
تاریخِ کلیسا میں لکھا ہے:
’’لفظ ایسٹر، اوسٹارا سے نکلا ہے جو صبح کی روشنی یا موسمِ بہار میں سورج کی واپسی کی جرمن دیوی تھی۔‘‘ (نشر ۱۴۵)
یعنی قدیم بت پرستی موسمِ بہار کی دیوی ایسٹر کا تہوار منایا کرتے تھے۔ مسیحیوں نے ان کے زیراثر مسیح کے مر کر جی اٹھنے کی یاد کو ایسٹر کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے یہ دن بھی موسمِ بہار ہی میں آتا ہے۔ خرگوش زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے موسمِ بہار کے مشابہ سمجھا جاتا تھا۔ مسیحی انڈے کو مسیحؑ کی قبر کے مماثل سمجھ کر ایسٹر کے دن خرگوش اور رنگے ہوئے یا سجائے ہوئے انڈے ایک دوسرے کو تحفتاً پیش کرتے یا ان سے کھیلتے ہیں۔ یہ دونوں رسوم بت پرست اقوام سے ماخوذ ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیں:
The Encyclopedia of Religion Editor in Chief Mircea Eliade 1987 Vol. 4 P. 558 Col. 1
ازروئے بائیبل یہودی مہینہ ابیب یا منسیان کی چودہ تاریخ کو مصلوب ہوئے تھے۔ یہودی مہینے چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، تاہم سارے شمسی سال میں گردش نہیں کرتے۔ مخصوص یہودی تقویم کی وجہ سے ابیب کی چودھویں تاریخ ۲۱، ۲۲ یا ۲۵ مارچ سے ۲۱ یا ۲۵ اپریل کے درمیان پڑتی ہے۔ یہودی ماہ ابیب موسمِ بہار کے انگریزی مہینوں مارچ اپریل میں پڑتا ہے۔ (مختلف ممالک میں ایسٹر مختلف دنوں کو منایا جاتا تھا)۔ مذکورہ تاریخوں اور اتوار کا تعین صدیوں کی بحث و تمحیص اور سوچ بچار کے بعد کیا گیا تھا۔ پہلے یہ تہوار آٹھ دن منایا جاتا تھا۔ گیارہویں صدی کے بعد تین دنوں تک محدود رہ گیا۔ ایسٹر پہلے چالیس روزے رکھنے کا رواج مسیحی کلیسا کے دوسرے دور ۳۱۳ء تا ۵۹۰ء میں پڑا۔ (نشر ۱۱۹)
القصہ مسیحیوں نے سورج پوجا کے زیراثر بت پرستیوں کا یہ تہوار اپنا لیا تھا۔ البتہ کاتھولک نقیب کا یہ کہنا غلط ہے کہ ’’مسیحیوں نے اس دیوی کو بھلا دینے کے لیے موسمِ بہار میں آنے والی عید کا نام ایسٹر رکھ دیا‘‘۔ کیونکہ اگر ایسٹر دیوی کو بھلانا مقصود ہوتا تو اس عید کا نام پھر سے ایسٹر نہ رکھتے، مسیح کے نام سے موسوم کرتے۔ اس تمام بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسٹر مسیح کی یاد میں نہیں منایا جاتا بلکہ ایسٹر دیوی کی یاد کو تازہ رکھنے کی عید ہے۔
مسیحی مشنریوں کی سرگرمیاں اور مسلم علماء اور دینی اداروں کی ذمہ داری
محمد عمار خان ناصر
برصغیر میں فرنگی استعمار کے تسلط کے دوران عیسائی تبلیغی مشنریوں کا اس خطہ میں سرگرم عمل ہونا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پادری فنڈر نے، جو کہ ایک امریکن نژاد کیتھولک پادری تھا، ان مشنریوں کی تحریک میں خصوصی کردار سرانجام دیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کے ساتھ اس پادری کا زبردست مناظرہ ہوا جس میں اس نے بائبل میں تحریف وغیرہ کا اقرار مجمع عام کے سامنے کر لیا۔ لیکن عیسائی مشنریوں نے اپنے اس سنہری دور میں اہم کامیابیاں حاصل کیں اور اس طرح انگریز اپنے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی پروردہ عیسائی مشنریوں کے قدم برصغیر میں جما کر چلا گیا۔
ان مشنریوں کی تبلیغ کے مختلف طریقہ کار ہیں جن میں سے ایک مؤثر ذریعہ ’’بائیبل کارسپانڈنس سکولز‘‘ کے عنوان سے بائیبل کی تشریح و توضیح پر مبنی لٹریچر عوام الناس تک پہنچانے کا ہے۔ اس ذریعہ سے آدمی کو آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور سادہ لوح اور دین سے بے بہرہ لوگ گمراہی کے اس عمیق گڑھے میں گرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ان سکولز اور اداروں کی کارکردگی کے بارے میں ڈاکٹر اے ایم شرگون رقمطراز ہیں:
’’ایک اور کوشش جو بہت سے ممالک میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے وہ بائیبل کارسپانڈنس کورس ہیں۔ ہندوستان میں یہ طریقہ اخباروں کے ذریعہ بشارتی کام سے شروع ہوا۔ اس کے اخبار ’’ہندو‘‘ اور دہلی کے اخبار ’’ہندوستان ٹائمز‘‘ میں مختلف مضامین اور اشتہار دیے گئے اور جن میں مذہب کے متعلق سوالات درج تھے اور مسیحیت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا گیا اور پڑھنے والوں کو دعوت دی گئی کہ اگر وہ اس کے بارے میں کچھ اور دریافت کرنا چاہتے ہوں تو بائیبل کارسپانڈنس کورس میں شامل ہو جائیں۔ ’’ہندوستان ٹائمز‘‘ میں ایسٹر کے متعلق ایک اعلان کی وجہ سے ایک سو عرضیاں ان لوگوں کو وصول ہوئیں جو اس کورس میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ ولور (Vilor) میں ڈاکٹر سٹینلی جونس کی میٹنگوں کے بعد ۴۵۰ درخواستیں وصول ہوئیں۔ یہ تحریک پھیلی اور زور پکڑتی گئی یہاں تک کہ اب یہ کورس ہندوستان اور سری لنکا میں تقریباً نو (۹) زبانوں میں دیے جا رہے ہیں۔ جنوبی ہندوستان کی کلیسا کے بشپ نیوبیگن (New Bagan) کہتے ہیں کہ مجھے کئی بائیبل کارسپانڈنس کورسوں کے بارے میں علم ہے، ان میں سے ایک کے تقریباً بارہ ہزار ممبر ہوں گے۔ یہ کورس بہت احتیاط سے تیار کیے جاتے ہیں اور اکثر اوقات مکمل ہونے کے لیے کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم محض تجسس کی وجہ سے یہ کورس شروع کرے تو وہ اکثر اسے پورا نہیں کر سکتا، کہیں اگر وہ یہ تمام کورس ختم کر لے تو اس کی زندگی پر ضرور ایک گہرا اثر پڑے گا۔ ایسے ایک طالب علم نے حال ہی میں ہمیں لکھا ہے ’’میں ہندو تھا لیکن اب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہوں اور بتسمہ پا لیا ہے‘‘۔ ایک اور چٹھی میں ایک ہائی سکول کے لڑکے نے کچھ اور کتابیں منگوائیں اور لکھا کہ امتحان ختم ہونے کے بعد میں ذاتی طور پر لکھنا چاہتا ہوں‘‘۔ یہ کورس بالکل ہی بائیبل سے لیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگوں کی توجہ انجیل کی طرف لگانے کا بہترین ذریعہ ہیں۔‘‘ (بشارت عالم میں بائیبل کا درجہ۔ مصنفہ اے ایم شرگون۔ مترجمہ مسز کے ایل ناصر ۔ مطبوعہ ۱۹۵۶ء ص ۲۰۹ و ۲۱۰)
پاکستان میں کم و بیش پندرہ بائیبل سکولز اپنے تمام تر اشاعتی و تبلیغی وسائل و ذرائع کے ساتھ مصروف العمل ہیں۔ ان کے سنٹرز یہ ہیں: فیصل آباد، لاہور، کراچی، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان، شکارپور، راولپنڈی، ایبٹ آباد، لاڑکانہ، ملیرپور۔ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ ’’توریت، زبور اور صحائف الانبیاء کا مطالعہ کیجئے‘‘۔ اور کبھی ’’صحت و ہیلتھ‘‘ کے عنوان سے اشتہار ہوتا ہے۔ سادہ لوح قارئین میں بعض تو سرے ہی سے ان ناموں سے ناواقف ہوتے ہیں اور بعض جن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتب فلاں فلاں نبی پر نازل ہوئی تھی، وہ تجسس و تعجب کے ساتھ ساتھ ’’بائیبل سکولز‘‘ کو ایک علمی و تبلیغی ادارہ سمجھتے ہوئے فورًا لٹریچر طلب کرتے ہیں۔ لٹریچر میں انتہائی ذہانت سے صرف تبلیغی انداز روا رکھا جاتا ہے۔ بعض مختلف فیہ مسائل مثلاً ’’اسماعیل کی قربانی‘‘ تورات وغیرہ کے بارے میں نظریہ کا کھل کر اظہار نہیں کیا جاتا۔ ویسے بھی یہ ایسے مسائل ہیں جن سے عوام عموماً ناواقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ قاری اور طالب علم یکطرفہ معلومات کے باعث لٹریچر کی تعلیم پر پوری طرح ’’راسخ‘‘ ہو جاتا ہے۔ خوبصورت اسناد اور عمدہ کتابیں بطور انعام حاصل کرنے والا طالب علم ’’جال‘‘ میں پھنس جاتا ہے۔ انجیل اور بائیبل عطا کرنے کے خوشنما وعدے تجسس کے مارے قاری کو کسی اور کام کا نہیں چھوڑتے۔ یہ بات واضح طور پر دیکھنے میں آئی ہے کہ مسلم عوام تو رہے ایک طرف بعض علماء بھی بائیبل کے بارے میں بڑے تجسس اور شوق کا شکار ہوتے ہیں اور بلاوجہ بائیبل کو اہمیت دیتے نظر آتے ہیں۔ ایسا شوق و ذوق عیسائیوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت کے مطالعہ میں نوعمر حضرات بائیبل کو قارون کا خزانہ سمجھتے ہیں اور ناجائز طور پر اس کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں (معاذ اللہ) لیکن جیسے ہی وہ بائیبل کی اصلیت و حقیقت کو سمجھتے ہیں ان کا جوش و جذبہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔۔۔
مسلم علماء و قائدین اپنے اس عیار و مکار دشمن سے بے خبر ہیں یا اس کی سازشوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس بارے میں بے حس ہیں۔ عوام کو کیا معلوم کہ بائیبل کیا ہے، اس کا مواد کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے۔ ہر آدمی بنی اسرائیل کی تاریک تاریخ سے واقف نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں مغربی ممالک کی امداد سے چلنے والے مشنری اداروں کے وظیفہ خوار شاطر اور مکار پادریوں کا گروہ ہر وقت دینِ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و منقبت کو سرِعام للکارا جاتا ہے جس کی تازہ مثال ۔۔۔ پادری برکت اے خان آف سیالکوٹ کی تصنیف ’’قیامت اور زندگی‘‘ ہے۔۔۔
’’کسی تحصیلدار کو سلام کرتے وقت کہیں گے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب سلام! تو وہ تحصیلدار فورًا سمجھ جائے گا کہ اس سلام کرنے والے شخص نے میرا مذاق اڑایا ہے کیونکہ میں ڈپٹی کمشنر نہیں ہوں یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اپنے دین کے بارے میں مبالغہ آمیزی کرتے ہیں کہ ہمارے ہادی نبیوں کے سردار ہیں، وہ محبوبِ خدا ہیں، وہ مقصودِ کائنات ہیں، وہ وجۂ تخلیق کائنات ہیں، وہ نبیوں کے سرتاج ہیں، وہ روزِ قیامت شفاعت کریں گے، سب نبی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مبالغہ کی حد ہو گئی۔‘‘ (ص ۱۱)
۔۔۔ یہ صورتِ حال علماء کرام اور دینی جماعتوں و اداروں کی خصوصی توجہات کی متقاضی ہے اور یقیناً ہماری دینی و ملی غیرت کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلم اکثریت کی موجودگی میں آقائے نامدار فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں برسرِعام گستاخی کی جائے اور مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے منظم ادارے سرگرم عمل ہوں، علماء کرام سے بصد ادب گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں ورنہ نئی نسل کی گمراہی کی ذمہ داری عند اللہ و عند الناس انہی پر ہو گی۔
تہذیبِ جدید یا دورِ جاہلیت کی واپسی
حافظ محمد اقبال رنگونی
’’فرانس میں ۱۹۸۰ء کی دہائی کے دوران جنم لینے والے بچوں کی ایک چوتھائی تعداد شادی کے بغیر پیدا ہوئی۔ قومی شماریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق ۱۹۸۸ء میں غیر شادی شدہ والدین کے ہاں دو لاکھ تیس ہزار بچے پیدا ہوئے جو کہ کل پیدائش کا چھبیس فیصد ہے۔ ۱۹۸۰ء میں یہ تعداد ۹۱ ہزار تھی۔‘‘ (روزنامہ جنگ ۔ ۱۱ فروری ۱۹۹۰)۔
برطانیہ کی اخلاقی حالت دیکھیئے:
’’برطانیہ میں اب ہر چار میں سے ایک بچہ غیربیاہتا والدین کے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ مرکزی دفتر شماریات نے برطانوی معاشرے کے بارے میں سالانہ سروے میں بتایا کہ غیربیاہتا جوڑوں کے ہاں پیدائش کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اگر یہ اضافہ اسی شرح سے جاری رہا تو چند سال کے عرصہ میں برطانیہ میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کے والدین غیر شادی شدہ ہوں گے۔‘‘ (روزنامہ جنگ ۔ ۱۵ فروری ۱۹۹۰ء)
برطانیہ میں بے غیرتی و بے شرمی کے مناظر اتنے عام ہیں کہ شرم و حیا کا نام لینا گویا ایک جرم ہو گیا ہے۔ عفت و عصمت کا تحفظ برطانوی معاشرہ میں ایک عجیب اور نرالا ہے اور جو کوئی اپنی عفت و عصمت کا تحفظ کرتا ہے اسے نادر خیال کیا جاتا ہے۔ ۹ مارچ کی رات برطانوی چینل ۱۲۷ میں ایک پروگرام دکھایا گیا جس کا موضوع ’’کیا مرد و عورت کا کنوارا ہونا ضروری ہے؟‘‘ تھا۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر نے ملک کے اکثر نوجوانوں سے انٹرویو لیے۔ ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ شادی سے پہلے اپنے کنوارے پن سے محروم ہو چکے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس بداخلاقی و بدکرداری کو بڑے فخریہ انداز میں سنا رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کا کہنا تھا کہ شادی سے قبل کسی لڑکے اور لڑکی کے لیے کنوارہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ پروگرام میں صرف ایک لڑکی ایسی دکھائی گئی جو ۳۱ سال کی ہونے کے باوجود ابھی تک کنواری تھی اور ہر سال اپنے ڈاکٹر سے کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ لیتی رہی ہے۔
علاوہ ازیں مانچسٹر ایوننگ نیوز ۲ فروری کی اشاعت میں خبر دیتا ہے کہ محکمہ صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت غیر شادی شدہ عورتیں زیادہ بچے پیدا کر رہی ہیں۔ ۱۹۸۸ء میں مانچسٹر کے ہسپتالوں میں جو بچے پیدا ہوئےہیں ان میں ۵۰ فیصد کنواری ماں سے پیدا ہوئے۔ مانچسٹر کے عیسائی پادری مسٹر سٹانلی بوتھ کلبورن نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں فیملی لائف کو بہتر بنانا ہو گا اور اس کے لیے شادی انتہائی ضروری ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کے رہنماؤں نے لوگوں کو تعلیم و تبلیغ دینی شروع کی ہے کہ شادی کیجئے اور اس کے لیے ۴۰ پادری ان موضوعات پر تبلیغ کرنے نکلے ہیں۔
یورپی تہذیب کے اثرات نے جب ایشیائی اور اسلامی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا اور یورپ کی اندھادھند تقلید ہونے لگی تو اس کا کتنا عبرتناک انجام سامنے آیا، اسے ایک رپورٹ میں دیکھیئے:
’’ایدھی ٹرسٹ کے بانی عبد الستار ایدھی کی اہلیہ نے اطلاع دی کہ پاکستان کے مختلف ایدھی سنٹروں کے ذریعے گذشتہ ماہ ۲۴۱ نوزائیدہ بچوں کی لاشیں ملی ہیں جنہیں دفنا دیا گیا۔ جبکہ گذشتہ ماہ کے دوران کراچی اور دیگر علاقوں سے ملنے والے ۳۲ زندہ نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کو لاوارث سنٹر میں پہنچایا گیا۔ بیگم ایدھی نے کہا کہ اس تعداد سے پاکستان کے عوام کو اندازہ کرنا چاہیئے کہ اس طرح نہ جانے کتنے معصوم بچے اپنے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے موت کی بھینٹ چڑھا دیے جاتے ہیں۔ بیگم ایدھی نے کہا کہ ایسے افراد جو اپنے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے ان معصوموں کو قتل کر دیتے ہیں ان سے بار بار اپیل کی گئی ہے کہ خدارا وہ اپنے گناہ اور جرم کو چھپانے کے لیے قتل جیسے سنگین جرم کے مرتکب نہ ہوں بلکہ ان بچوں کو ہمارے سنٹروں میں دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ایسے چار ہزار بچے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے بے اولاد پاکستانی جوڑوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔‘‘ (روزنامہ جنگ ۔ ۹ فروری ۱۹۹۰ء)
ایدھی ٹرسٹ کے ایک مختصر اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ملک میں ہزاروں کی تعداد میں نوزائیدہ بچوں کو یا تو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے یا پھر کسی گلی کے کنارے بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسلامی قوانین سے انحراف اور یورپی تقلید کے نتائج ہیں جس نے نہ صرف زنا جیسے خبیث جرم پر آمادہ کیا بلکہ معصوم نوزائیدہ بچوں کو قتل کرانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یورپ کی دنیا میں ایسے لوگوں کی کافی تعداد موجود ہے جو بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہی ہے مگر انہوں نے اپنے بچوں کو قتل نہیں کیا۔ وہ تو کنواری ماں کے لقب سے ملقب ہو کر بے شمار منافع بھی حاصل کرتی ہیں لیکن اپنے ملک میں یورپ کی تقلید پر فخر کرنے والیوں کو کنواری ماں بننا پسند نہیں، بچوں کو اپنی گود میں رکھنا منظور نہیں۔ تقلید کرنی ہے تو پھر پوری تقلید کیجیئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ تہذیبِ یورپ کے عاشق ہیں۔ ہم تو ایسی تہذیب کے بارے میں یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ؎
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں
نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے
دورِ جاہلیت کی واپسی
ایرانی نژاد برطانوی رپورٹر بضیوفت کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں عراق نے موت کی سزا دے دی اور جاسوسی کرانے میں مدد کرنے والی برطانوی نرس کو ۱۵ سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اس اعلان کے بعد برطانیہ اور یورپی پارلیمنٹ نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا اور عراق کے اس اقدام کی سخت مذمت کی گئی۔
جہاں تک بضیوفت کے اسرائیلی جاسوس ہونے کا تعلق ہے، خود اس کے اعتراف کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں رہتی تاہم برطانیہ کے بعض ممبران پارلیمنٹ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اسے ایک مجرم قرار دیتے ہیں حتٰی کہ برطانوی دارالعوام میں اس امر پر بھی بحث کی جا رہی ہے کہ بضیوفت خود ایک عادی مجرم ہے اور اس نے ایک برطانوی بینک کو بم کے ذریعے لوٹنے کی بھی کوشش کی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانوی وزیراعظم اور دیگر وزراء سزائے موت کے خلاف اپنا احتجاجی بیان دے رہے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر یہ ہی جملہ جاری ہے کہ یہ مہذب دور ہے Civilized World اور ایسی دنیا میں اس قسم کی کارروائی پر سزائے موت کا حکم دے کر فورًا عمل کرنا عراق کا بدترین فعل ہے اور عراق ابھی تک دورِ جاہلیت میں ہے۔ برطانوی وزیراعظم کہتی ہیں کہ ’’عراقی حکومت کا یہ اقدام بربریت ہے جو دنیا کے تمام مہذب لوگوں کے خلاف ہے۔‘‘
اس واقعہ کے فورًا بعد برطانوی پریس اور ٹیلیویژن نے عراق کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور آپ جانتے ہیں کہ برطانوی پریس اور ٹیلیویژن اس معاملے میں کتنا ماہر ہے۔ چنانچہ عراقی صدر کے ظلم و ستم کی داستانیں باتصویر سامنے آنے لگیں اور یہ ثابت کر دکھا دیا گیا کہ عراق ایک ظالم ملک ہے اور اس کے اعلیٰ افراد وہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔
ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ بضیوفت کو جو سزائے موت سنائی گئی ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ جاسوسی کرنے کے جرم میں دنیا کے ممالک نے کیا سزا رکھی تھی اور آج کیا ہے؟ عراقی قانون میں اس کا کیا حکم ہے؟ امریکہ کیا کہتا ہے؟ روس نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل کیا کرتا ہے؟ اور خود برطانیہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ قانون دان حضرات بخوبی اس سے واقف ہیں۔ ہم صرف برطانوی وزیراعظم اور دیگر وزراء کے اس دعوٰی پر کہ ’’آج کا دور ایک مہذب دور ہے‘‘ پر ایک سرسری نظر دوڑانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ واقعتاً دورِ حاضر مہذب دور ہے یا دورِ جاہلیت کا ایک عکس ہے جو صرف نام بدل کر یورپ کی دنیا میں داخل ہوا ہے۔
برطانوی مفکروں کے نزدیک تہذیب اور مہذب کا کیا معنٰی و مفہوم ہے؟ یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ مندرجہ ذیل امور کو تہذیب اور مہذب دنیا کا نام دیا جا سکتا ہے؟
- یورپ میں ایک ایک دن میں ہزاروں غیر شادی شدہ والدین کے ہاں اولاد ہونا مہذب دنیا ہے؟
- یورپ میں لواطت پرستی کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب، مالی تعاون، حوصلہ افزائی اور بڑے بڑے سنٹر کھولے جاتے ہیں۔
- یورپ میں ایک ۸ سالہ بچی سے لے کر ایک ۸۰ سالہ بوڑھی تک کی عصمت کا محفوظ نہ ہونا بھی تہذیب یافتہ دنیا کا کارنامہ ہے۔
- یورپ میں ۵ سالہ بچی سے لے کر ۹۵ سالہ بوڑھی پر مجرمانہ حملہ کر کے خون میں نہلا دینا بھی مہذب دور کا ایک ادنٰی کرشمہ ہے۔
- یورپ میں زنا، بے حیائی، بے شرمی اور اخلاقی زبوں حالی بھی مہذب دنیا کا تحفہ ہے۔
- یورپ میں شراب اور منشیات کا کثیر استعمال اور اس سے روحانی و جسمانی جرائم بھی تہذیبِ جدید کا پیدا کردہ ہے۔
- ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو موت کی آغوش میں پہنچا دینا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرنا آج کی دنیا کا کمال ہے۔
- چوری، دن دہاڑے ڈکیتی، راہ چلتی بوڑھی عورت کو چاقو دکھا کر رقم لوٹ لینا، اسے زخمی کر دینا بھی دورِ حاضر کا ایک فیشن ہے۔
- با حیا اور عصمت و عصمت کا تحفظ کرنے والوں کو طرح طرح سے بے شرمی پر ابھارنا اور اس کے عنوان کی ترغیب دینا بھی تہذیب ہے۔
مولانا (الطاف حسین) حالیؒ نے دورِ جاہلیت کا جو نقشہ اپنی مسدس میں کھینچا ہے اگر دیکھا جائے تو آج کے دور پر بالکل صادق ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ؎
بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں
کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں
نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں
نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں
لیا عقل و دیں سے نہ کچھ کام انہوں نے
کیا دینِ برحق کو بدنام انہوں نے
فرمائیے! دورِ جاہلیت اور مہذب دنیا میں کیا فرق رہا؟ نام کے بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ درحقیقت یہ مہذب دور نہیں بلکہ دورِ جاہلیت ایک نیا عنوان لے کر سامنے آیا ہے۔
پاکستان میں نفاذ اسلام کی جدوجہد اور علماء کرام کی ذمہ داریاں
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ۱۹۴۷ء میں ’’لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ‘‘ کے اجتماعی ورد کی فضا میں اس مقصد کے لیے عمل میں آیا تھا کہ اس خطہ کے مسلمان الگ قوم کی حیثیت سے اپنے دینی، تہذیبی اور فکری اثاثہ کی بنیاد پر ایک نظریاتی اسلامی ریاست قائم کر سکیں۔ لیکن تینتالیس سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود دستور میں ریاست کو ’’اسلامی جمہوریہ پاکستان‘‘ کا نام دینے اور چند جزوی اقدامات کے سوا اس مقصد کی طرف کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جبکہ تحریکِ آزادی اور تحریکِ پاکستان کے لاکھوں شہداء کی ارواح ہنوز اپنی قربانیوں کے ثمر آور ہونے کی خوشخبری کی منتظر ہیں۔
ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی حیثیت سے ’’اسلامی جمہوریہ پاکستان‘‘ کی تشکیل کا تقاضا یہ تھا کہ فرنگی استعمار نے نوآبادیاتی مقاصد کے لیے اس خطہ میں جو سیاسی، قانونی، معاشرتی اور معاشی نظام مسلط کیا تھا اس پر نظرثانی کر کے اسے اسلام کے سنہری اور ابدی اصولوں کی بنیاد پر ازسرنو منظم و مرتب کیا جاتا۔ اور سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کی شکست کے اس دور میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کر کے نہ صرف عالمِ اسلام بلکہ پوری دنیا کی ایک فلاحی اور عادلانہ نظام کی طرف راہنمائی کی جاتی۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا اور پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنانے کا خواب تعبیر کی منزل سے کوسوں دور دکھائی دے رہا ہے۔
پاکستان کے عوام اسلام کے ساتھ سچی اور والہانہ وابستگی رکھتے ہیں اور یہاں کے دینی حلقوں کی جڑیں عوام میں مضبوط اور گہری ہیں لیکن اس کے باوجود نوآبادیاتی نظام کے خاتمہ اور اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کا مقصد تشنۂ تکمیل کیوں ہے؟ یہ سوال گہرے تجزیہ اور غور و فکر کا متقاضی ہے اور پاکستان کے دینی حلقوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کر کے اس کی روشنی میں اپنے کردار اور طرزِ عمل کا جائزہ لیں اور روایتی طریق کار پر اڑے رہنے کی بجائے اجتہادی اور انقلابی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نفاذِ اسلام اور غلبۂ شریعت کی جدوجہد میں اپنے کردار کا ازسرنو تعین کریں۔
یہ درست ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ملک کی باگ ڈور ایسے طبقہ کے ہاتھ میں آئی جو فکری اور عملی طور پر اسلامی نظام کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھا اور اس کی تعلیم و تربیت نوآبادیاتی دور میں بدیشی آقاؤں کے مسلط کردہ تربیتی نظام کے تحت اور اسی کے مخصوص مقاصد کے لیے ہوئی تھی، اس لیے اس طبقہ سے شریعتِ اسلامیہ کے نفاذ کی توقع ہی عبث ہے۔
یہ بھی درست ہے کہ ایک نظام کی تبدیلی اور دوسرے نظام کے عملی نفاذ کے لیے جس اجتماعی فکری کام کی ضرورت تھی اس کا ہمارے ہاں فقدان رہا ہے۔ ہماری دینی تعلیم گاہوں میں اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے نہیں پڑھایا گیا اور اسلامی نظام کو عملاً چلانے کے لیے تربیت یافتہ افراد کار کی فراہمی کی طرف کوئی شعوری توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کیے گئے چند جزوی اقدامات بھی عملدرآمد کی کسوٹی پر پورے نہیں اتر سکے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے سب سے مؤثر تین طبقوں سرمایہ دار، جاگیردار اور نوکر شاہی کے مفادات اسلامی نظام سے متصادم ہیں اس لیے ان کی اجتماعی قوت نفاذِ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے جس کی موجودگی میں ملک کے اجتماعی نظام کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نفاذِ اسلام کی راہ میں ان تینوں بڑی رکاوٹوں کے وجود اور اس کے تسلسل کا سب سے بڑا سبب دینی حلقوں کی بے تدبیری، باہمی عدم ارتباط اور حقیقی مسائل سے بیگانگی کا طرزِ عمل ہے جس نے ان رکاوٹوں کے شجر خبیثہ کی مسلسل ۴۲ سال تک آبیاری کر کے اسے تن آور درخت بنا دیا ہے۔
پاکستان اہل السنۃ والجماعۃ کی غالب اکثریت کا ملک ہے، اہل السنۃ والجماعۃ کے تینوں مکاتب فکر دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے اکابر علماء نے تحریک پاکستان میں قائدانہ حصہ لیا ہے اور ایک پلیٹ فارم پر تشکیلِ پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اگر یہ تینوں مکاتبِ فکر قیام پاکستان کے بعد بھی اجتماعیت اور اشتراکِ عمل کے جذبہ کو برقرار رکھتے ہوئے:
- مشترکہ سیاسی دباؤ منظم کر کے نفاذِ اسلام کی راہ میں حائل طبقوں کا جرأت کے ساتھ سامنا کرتے،
- دینی درسگاہوں میں اسلام کو ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پڑھا کر نفاذِ اسلام کے لیے افرادِ کار کی کھیپ تیار کرتے،
- اسلام دشمن لابیوں کی طرف سے اسلامی نظام کے بارے میں پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے مشترکہ جدوجہد کرتے،
- اور باہمی اعتماد و اشتراک اور تعاون کے ساتھ قوم کو ایک مشترکہ نظریاتی قیادت فراہم کرتے
تو مذکورہ بالا رکاوٹوں میں سے کوئی ایک رکاوٹ بھی ان کی اجتماعی قوت کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی سے دینی حلقے ایسا نہیں کر سکے بلکہ انہیں منصوبہ اور سازش کے تحت باہمی اختلافات و تعصبات کی ایک ایسی جنگ میں الجھا دیا گیا کہ گروہی تشخص اور انا کے سوا دین و دنیا کا کوئی اجتماعی مسئلہ ان کے ادراک و شعور کے دائرہ میں جگہ نہ پا سکا اور فرقہ وارانہ اختلافات میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا ذوق ہی دینی جدوجہد کی معراج بن گیا۔ یہ دینی حلقوں کی بے توجہی، بے تدبیری، عدم ارتباط اور حقیقی مسائل سے اعراض ہی کے ثمرات ہیں کہ:
- معاشرہ بے حیائی، بے پردگی اور مغرب زدہ معاشرت کی آماجگاہ بن گیا ہے،
- قرآن و سنت اور چودہ سو سالہ اجماعی تعامل کے برعکس عورت کی حکمرانی مسلّط ہوگئی ہے،
- قومی پریس میں قرآن و سنت کے صریح احکام کے خلاف بیانات چھپ رہے ہیں،
- قرآنی احکام کو نام نہاد انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے اجتہاد کے نام پر قرآنی احکام کو مغربی ذوق کے مطابق تبدیل کرنے کی تجاویز کھلم کھل سامنے آرہی ہیں،
- اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ دینی تشخص کی حامل سیاسی جماعتیں بھی اسلامی نظام کی بات غیر اسلامی نظاموں کی اصطلاحات اور حوالوں سے کرنے پر مجبور ہیں۔
حالات کے اس حد تک بگڑ جانے میں اگر ذمہ داری کا تعین کیا جائے تو دینی حلقے اس میں سرفہرست ہیں اور جب تک اس ذمہ داری کا ادراک اور احساس اذہان و قلوب میں اجاگر نہیں ہوتا اس وقت تک اصلاحِ احوال کی کوئی صورت بھی ممکن اور قابلِ عمل نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنانے کی راہ میں حائل مذکورہ رکاوٹیں آج بھی لاعلاج نہیں ہیں اور ان کی قوت آج بھی دینی حلقوں کی اجتماعی قوت کے سامنے ناقابل شکست نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے تینوں مکاتب فکر کے علماء کرام گروہی تشخصات اور تعصبات کے دائرہ سے نکل کر باہمی اشتراکِ عمل کو فروغ دیں اور ایک ایسا فکری، علمی اور دینی پلیٹ فارم قائم کریں جو ان مسائل کے ادراک اور تجزیہ کے ساتھ ساتھ اجتماعی فکری راہنمائی اور مذہبی و عوامی حلقوں کی ذہن سازی کا کردار ادا کر سکے۔ اس پلیٹ فارم کا عملی سیاسی گروہ بندی سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ خالص دینی اور علمی بنیاد پر اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتے ہوئے قوم کی راہنمائی کا فریضہ سرانجام دے۔ علماء کرام اس نوعیت کا پلیٹ فارم قائم کر کے جب عملاً آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ قوم کو فکری انتشار اور سیاسی انارکی کی اس دلدل سے نکالنے کی کوئی راہ تلاش نہ کر سکیں جس نے اس وقت قوم کے ہر ذی شعور فرد کو پریشانی اور اضطراب سے دوچار کر رکھا ہے۔
دینی شعائر کے ساتھ استہزاء و تمسخر کا مذموم رجحان
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
استہزاء کی بیماری اب یہود و نصارٰی سے نکل کر مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے۔ مختلف موضوعات پر کارٹون بنانا، ڈرامے پیش کرنا، نمازیوں کا تمسخر اڑانا اور عبادت کو کھیل کے طور پر پیش کرنا اس کے سوا کیا ہے کہ دین کے ساتھ استہزاء ہے۔ حج جیسی بلند عبادت کو فلم کے طور پر پیش کرنا شعائر اللہ سے تمسخر ہی تو ہے۔ صدر ایوب کے زمانے میں روزنامہ مشرق میں پڑھا تھا کہ مظفر نرالا نامی فلم ایکٹر کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کے کان میں مرغ کی اذان دلوائی۔ نومولود کے کان میں اذان کہنا سنت ہے مگر اس شخص نے اس سنت کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح لافنگ گیلری والوں نے ڈاڑھی کو استہزاء کا نشانہ بنایا ہے حالانکہ ڈاڑھی سنتِ انبیاءؑ ہے۔ جو خود تارکِ سنت ہے اسے خود کم از کم سنت کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔
پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ گورنر عباد خراسان کے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک منہ پھٹ شاعر بھی تھا۔ چلتے وقت عباد کی لمبی ڈاڑھی خوب ہلتی تھی، اس پر شاعرنے مزاحیہ شعر کہہ دیا۔ گورنر کو علم ہوا تو اس نے شاعر کو سخت سرزنش کی اور اسے پانچ ماہ تک پنجرے میں بند رکھنے کی سزا دی۔ گورنر اگرچہ خود زیادہ عادل تو نہیں تھا لیکن اس نے ڈاڑھی کی توہین کو برداشت نہ کیا۔ وہ شعر یہ تھا:
الا لیت اللحی کانت حشیشًا
فنعلفھا خیـــول المسلمین
ترجمہ: ’’کاش یہ ڈاڑھیاں گھاس ہوتیں تو ہم انہیں مسلمانوں کے گھوڑوں کو کھلاتے۔‘‘
یہودیوں کا یہ خاص شیوہ ہے کہ وہ اسلام اور اہلِ اسلام کی تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانتے دیتے۔ انہوں نے سیمسن اینڈ ڈیلائلہ کے نام سے پیغمبروں کی فلم بنا دی۔ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فلم میں پیش کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ استہزاء ہے جو کہ بہت ہی قبیح حرکت ہے۔ بدر کی جنگ کو فلم کے ذریعے پیش کیا۔ ارکانِ حج فلمائے گئے اور لوگ خوش ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے ٹریننگ ہوتی ہے اہلِ اسلام کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ سب یہود و نصارٰی کے نقشِ قدم پر شعائر اللہ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ کام خود مسلمان انجام دے رہے ہیں جو کہ دین کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والی بات ہے۔
تو فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ اس کو ٹھٹھا اور کھیل بناتے ہیں ’’ذلک بانھم قوم لا یعقلون‘‘ یہ اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے وگرنہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرتا ہو۔ اذان، نماز، حج وغیرہ تو شعائر اللہ ہیں، ان کی بے حرمتی تو احمق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ’’من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب‘‘ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل تقوٰی سے لبریز ہے۔ اور ظاہر ہے جو تمسخر کرے گا وہ تقوٰی سے بالکل عاری ہو گا۔
امریکہ اور کینیڈا کے یہودیوں نے اسلامی شعائر کو بہت حد تک تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کپڑے پر کلمہ طیبہ پرنٹ کر دیا۔ ماچس کی ڈبیہ پر لکھ دیا تاکہ اس کی بے حرمتی ہو۔ قمیص کے پچھلے حصے پر آیت الکرسی چھاپ دی جو بیٹھنے کے وقت نیچے آجائے۔ ایک بدبخت نے اونٹ کا نام محمدؐ رکھ دیا۔ ایک انگریز نے حضرت علیؓ کو لنگور کے نام سے موسوم کیا۔ غرضیکہ یہ لوگ اسلام اور اہلِ اسلام کی توہین، تمسخر اور ٹھٹھا کرنے سے باز نہیں آتے اور مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی اس روش پر چل نکلے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کا اجلاس
شیخ الحدیث حضرت سرفراز خان صفدر کے تاثرات
ادارہ
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی، اٹاوہ، جی ٹی روڈ، گوجرانوالہ کی انتظامیہ اور خصوصی معاونین کا ایک اہم اجلاس ۲۶ مارچ ۱۹۹۰ء مطابق ۲۸ شعبان المعظم ۱۴۱۰ھ شام پانچ بجے سائٹ آفس میں منعقد ہوا جس کی صدارت یونیورسٹی کے سرپرستِ اعلٰی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدظلہ العالی نے کی۔ عصر کی نماز سائٹ آفس کے سامنے گراؤنڈ میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی امامت میں ادا کی گئی اور اس کے بعد مولانا زاہد الراشدی، الحاج میاں محمد رفیق، اور جناب محمد سلیم (آرکیٹیکٹ) نے شرکاء اجلاس کو منصوبہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔
مولانا زاہد الراشدی نے بتایا کہ گذشتہ پانچ سال کے دوران زمین کی خریداری اور دیگر انتظامی، تعمیری اور اشاعتی امور پر اب تک کم و بیش انتالیس لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں جس کے تحت اس وقت ساڑھے بتیس ایکڑ (دو سو ساٹھ کنال) زمین حاصل کرنے کے علاوہ آفس بلاک کی تعمیر مکمل کی جا چکی ہے اور پہلے تعلیمی بلاک کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سارے اخراجات اصحابِ خیر کے تعاون سے پورے کیے گئے ہیں اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی سرکاری گرانٹ نہ لینے کا بنیادی پالیسی کے طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔
الحاج میاں محمد رفیق (صدر انتظامیہ) نے بتایا کہ اٹاوہ ریلوے کراسنگ سے شاہ ولی اللہ یونیورسٹی تک ڈسٹرکٹ کونسل نے جس پختہ سڑک کی منظوری دی تھی اس کا کام شروع ہو چکا ہے اور چند روز تک مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ کے مخیر احباب نے ہمارے ساتھ اس مشن میں جو مخلصانہ تعاون کیا ہے اس کی برکت سے ہم اس مرحلہ تک پہنچے ہیں اور اب تعلیمی بلاک کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، اس لیے احباب کو پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیئے اور اس کارِ خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیئے۔
یونیورسٹی انتظامیہ کے خازن الحاج شیخ محمد یعقوب نے بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً تین لاکھ روپے کی رقم موجود ہے جبکہ تعمیری پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ جناب محمد سلیم (آرکیٹیکٹ) نے بتایا کہ پہلا تعمیری بلاک، جس کی بنیادوں کی کھدائی ہو چکی ہے، دو منزلہ ہو گا جس میں اٹھارہ کلاس رومز اور اساتذہ کے پندرہ کمرے ہوں گے۔ یہ بلاک تقریباً ستر لاکھ روپے کی لاگت سے ایک سال میں مکمل ہو گا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے ماسٹر پلان اور تعلیمی بلاک کے بارے میں تفصیلات بیان کیں اور اس سلسلہ میں شرکاء اجلاس کے سوالات کے جوابات دیے۔
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ کے عہدہ داروں، اراکین اور معاونین کو شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے منصوبہ میں مرحلہ وار پیشرفت اور تعمیری کام کے باقاعدہ آغاز پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کی تعمیر آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید علوم اور زبانوں سے علماء کا واقف ہونا ازحد ضروری ہے کیونکہ موجودہ دور میں دنیا بھر میں تمام طبقات تک اسلام کا پیغام پہنچانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے اپنے دورۂ برطانیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے چند سال قبل برطانیہ کے مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا اور متعدد برطانوی باشندوں سے بات چیت ہوئی، ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے برطانیہ کے معاشرہ کو کیسا پایا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہاں جسم کے لیے تو ہر قسم کی سہولت مہیا کی گئی ہے لیکن روح کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس بات سے اس نے اتفاق کیا۔ یہ گفتگو ترجمان کے ذریعے ہوئی کیونکہ میں انگریزی زبان سے واقف نہیں۔ اس موقع پر مجھے محسوس ہوا کہ اگر مجھے انگریزی زبان سے واقفیت ہوتی تو میں اسلام کی زیادہ بہتر انداز میں ترجمانی کر سکتا تھا۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیئے اور شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے قیام کا ایک مقصد اس کمی کو دور کرنا بھی ہے۔
حضرت شیخ الحدیث نے اصحابِ ثروت پر زور دیا کہ وہ اس اہم مشن کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں۔
شریعت کا نظام اس ملک میں اک بار آنے دو
سرور میواتی
وطن میرا ہوا آزاد اب آزاد ہوں میں بھی
مجھے اپنے وطن میں جشنِ آزادی منانے دو
غلامی کے گذشتہ مرثیے پڑھنے سے کیا حاصل؟
کھلے دل سے ترانے مجھ کو آزادی کے گانے دو
منافع بے ملاوٹ حسبِ مرضی مل نہیں سکتا
مجھے بے خوف ہر خالص کو ناخالص بنانے دو
گھریلو تربیت میں بھی نہ ہو جائے کہیں غفلت
بلاناغہ حسیں چہروں کو ٹی وی پر دکھانے دو
برات اب آنے والی ہے یہاں میرے بھتیجے کی
درِ مسجد پہ بے چون و چرا باجا بجانے دو
بلا رشوت ملازم کا گزارا ہو نہیں سکتا
انہیں مِن فضلِ رَبی کی کمائی سے بھی کھانے دو
یہ آزادی کے رسیا بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے
یہ چوپائے کھڑے ہو کر ہی کھاتے ہیں تو کھانے دو
وہ دو شیزائیں دیکھو بیٹھ کر جانے لگیں بس میں
ہمیں بھی سیٹ پر ان کے مقابل بیٹھ جانے دو
لٹا کر اپنا سب کچھ تب کہیں جا کر بنا ممبر
مزے مجھ کو بھی عیشِ جاودانی کے اٹھانے دو
رہیں محروم کیوں اس نعمتِ عظمٰی سے مولانا
انہیں مادام کی دُھن میں نئی نعتیں سنانے دو
مٹھائی، کھیر، حلوہ روز کھانا بن گئی فطرت
انہیں مسجد میں ہر ہفتہ کسی کا دن منانے دو
جھنجوڑا کارواں نے جب تو میرِ کارواں بولے
ابھی کچھ اور دن کم بخت گل چھرے اڑانے دو
جرائم بڑھتے جاتے ہیں کمی ہونے نہیں پاتی
رئیس الملک کے اغماض پر آنسو بہانے دو
یہ سب بیماریاں ہو جائیں گی یکم رفوچکر
شریعت کا نظام اس ملک میں اک بار آنے دو
آپ نے پوچھا
ادارہ
مروجہ جمہوریت اور اسلام
سوال: عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے جمہوری نظام پیش کیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کیا موجودہ جمہوریت اسلام کے مطابق ہے؟ (محمد الیاس، گوجرانوالہ)۔
جواب: جمہوری نظام سے مراد اگر تو یہ ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیئے تو یہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ
’’تمہارے اچھے حکمران وہ ہیں جو تم سے محبت کریں اور تم ان سے محبت کرو، اور برے حکمران وہ ہیں جو تم سے بغض رکھیں اور تم ان سے بغض رکھو، وہ تم پر لعنت بھیجیں اور تم ان پر لعنت بھیجو۔‘‘
اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ضروری ہے اور اس عوامی اعتماد کے اظہار کی جو صورت بھی حالات کے مطابق اختیار کر لی جائے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن جمہوریت کا جو تصور آج کل معروف ہے اور جس میں عوام کے نمائندوں کو ہر قسم کے کُلّی اختیارات کا حامل سمجھا جاتا ہے، یہ اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے۔ علامہ سید سلیمان ندویؒ نے ۱۴ مارچ ۱۹۲۶ء کو کلکتہ میں جمعیۃ العلماء ہند کے سالانہ اجلاس کے موقع پر اپنے خطبۂ صدارت میں اسلام اور مروجہ جمہوریت کے درمیان اصولی فرق کو ان الفاظ کے ساتھ واضح کیا ہے:
’’موجودہ جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں کچھ فرق بھی ہے۔ موجودہ جمہوریت کے لیے شریعتِ الٰہی سے واقفیت ضروری نہیں۔ اسلامی جمہوریت کی صدارت کے لیے دوسرے شرائط کے ساتھ شریعتِ الٰہی سے واقفیت ضروری ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ راویوں کی اکثریت اور قلت غلطی اور صواب کا معیار نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت سے قریب ہونا یا نہ ہونا صحت اور خطا کی پہچان ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ارکانِ سلطنت جس طرح رومن لاء اور یورپین قوانین سے واقف ہیں وہ اسلامی قوانین سے بھی آگاہ ہوں، بلکہ وہ جس طرح قوانینِ یورپ کے ماہر ہیں اگر وہ اسلامی قانون اور اس کے مآخذ سے بھی آگاہ ہوں تو وہ خود علماء ہیں۔ ان کو تنگ خیال ’’ملاؤں‘‘ کی بھی شکایت نہیں رہے گی اور ان کو مذہب یا تمدن کی کشمکش سے نجات مل جائے گی۔‘‘
نواب سراج الدولہؒ کون تھا؟
سوال: تحریکِ آزادی کے حوالہ سے نواب سراج الدولہؒ کا ذکر اکثر مضامین میں ہوتا ہے۔ یہ بزرگ کون تھے اور تحریکِ آزادی میں ان کا کردار کیا ہے؟ (حافظ عزیز الرحمان، گکھڑ)
جواب: جب انگریز برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش میں اپنے قدم جمانے میں مصروف تھا، نواب سراج الدولہؒ بنگال کا حکمران تھا اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے میدانِ جنگ میں انگریز کی قوت کو للکارا اور مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا۔ سراج الدولہ کو اس کے مرحوم والد علی وردی خان نے وصیت کی تھی کہ بنگال میں انگریزوں کو قدم جمانے کا موقع نہ دینا۔ چنانچہ سراج الدولہؒ نے اپنے والد کی جگہ حکمرانی کا منصب سنبھالتے ہی انگریزوں کو اپنے علاقہ میں قلعے اور مورچے توڑ دینے کا حکم دیا اور حکم نہ ماننے کی وجہ سے حملہ کر کے کلکتہ شہر لڑائی کے ذریعے انگریزوں سے چھین لیا۔
اس کے بعد پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہؒ اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں سراج الدولہؒ کے سپہ سالار میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ سازباز کر کے سراج الدولہؒ سے غداری کی اور اس غداری کے نتیجے میں نواب سراج الدولہؒ ۲۹ جون ۱۷۵۷ء کو پلاسی کے میدانِ جنگ میں جامِ شہادت نوش کر گئے۔ اور اس طرح فرنگی استعمار کے خلاف یہ پہلا جہادِ آزادی تھا جو نواب سراج الدولہؒ کی قیادت میں پلاسی کے میدان میں لڑا گیا مگر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔
حج بدل کون کرے؟
سوال: عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جس شخص نے اپنا حج کیا ہو وہی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ کیا شرعاً یہ ضروری ہے؟ (محمد سلیمان۔ لاہور)
جواب: امام شافعیؒ کے نزدیک حج بدل کے لیے یہ شرط ہے کہ وہی شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو مگر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے اور ان کے نزدیک وہ شخص بھی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا۔ البتہ علامہ شامیؒ (رد المحتار ج ۲ ص ۲۴۸) میں فرماتے ہیں کہ اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ حج بدل کے لیے اسی شخص کو بھیجا جائے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’قرآن معجزۂ جاوداں‘‘
تصنیف: ڈاکٹر احمد دیدات
اردو ترجمہ: عنایت اللہ
صفحات ۱۲۴
ملنے کا پتہ: الکتاب والسنۃ لائبریری، چونیاں سٹی، ضلع قصور
جناب ڈاکٹر احمد دیدات مسیحیت کے موضوع پر عالمی شہرت کے حامل محقق اور مناظر ہیں۔ انہوں نے نامور عیسائی علماء کے ساتھ مناظروں میں اسلام کی حقانیت اور بائبل کے محرف ہونے پر ناقابل تردید دلائل و شواہد پیش کر کے اہلِ علم سے خراجِ تحسین وصول کیا ہے اور ان موضوعات پر متعدد کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ زیرِ نظر کتابچہ میں ڈاکٹر احمد دیدات نے قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر ریاضی کے حوالے سے بحث کی ہے اور اعداد و شمار کے فارمولوں کے ذریعے قرآن کریم کے اعجاز کے ایک نئے پہلو کو متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔
قرآن کریم بلاشبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس کے اعجاز کے متنوع پہلوؤں پر بحث و تمحیص کا سلسلہ اہلِ علم کے ہاں صدیوں سے جاری ہے اور اعداد و شمار کے حوالہ سے یہ کوشش بھی اسی علمی بحث کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ’’الشریعہ‘‘ کے گذشتہ شمارہ میں محترم جناب پروفیسر غلام رسول عدیم کے مفصل مضمون کے ذریعے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کے ’’عددی اعجاز‘‘ کی یہ بحث بوجوہ محلِ نظر اور پُر از خطر ہے۔ بالخصوص اس کا یہ پہلو بطورِ خاص قابلِ توجہ ہے کہ ۱۹ کے عدد کے حوالہ سے قرآن کریم کے عددی اعجاز کی یہ بحث امریکہ کے ڈاکٹر رشاد خلیفہ نے شروع کی ہے جس کا محترم ڈاکٹر احمد دیدات نے زیرنظر رسالہ میں جابجا حوالہ دیا ہے اور قارئین کو ڈاکٹر رشاد خلیفہ کے مضامین کے مطالعہ کا مشورہ بھی دیا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر رشاد خلیفہ کا اپنا حال یہ ہے کہ اس نے ۱۹ کے اسی عددی فارمولا کی بنیاد پر نہ صرف احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے کر معاذ اللہ انہیں ناقابلِ اعتبار ٹھہرایا ہے بلکہ قرآنِ کریم کی بعض آیات کو بھی الحاقی قرار دینے کی جسارت کر ڈالی ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ ڈاکٹر رشاد خلیفہ نے خود رسول ہونے کا دعوٰی کیا اور سالِ رواں کے آغاز میں قتل ہو گیا۔
اسی پس منظر میں ہمارے نزدیک قرآن کریم کے عددی اعجاز کی یہ بحث خطرات سے خالی نہیں ہے اور ہماری معلومات کے مطابق خود ڈاکٹر احمد دیدات بھی اس سے رجوع کر چکے ہیں۔ اس لیے جو ادارے یا حضرات اس قسم کے مضامین شائع کر رہے ہیں ان کے دینی جذبہ کا اعتراف اور احترام کرنے کے باوجود ہم انہیں مخلصانہ مشورہ دیں گے کہ وہ ’’عددی اعجاز‘‘ کے خوشنما کیپسول میں بند قرآنی آیات اور احادیثِ نبویؐ کے انکار کے اس زہر کو مزید پھیلانے سے گریز کریں۔ امید ہے کہ متعلقہ حضرات اور ادارے ہماری اس گذارش پر سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں گے۔
’’شمالی علاقوں کی آئینی حیثیت اور مسئلہ کشمیر‘‘
منجانب: تنظیم تحفظ آئینی حقوق شمالی علاقہ جات
صفحات: ۲۸
ملنے کا پتہ: جامعہ اسلامیہ سیٹلائیٹ ٹاؤن اسکردو
گلگت، بلتستان، دیامر اور دیگر ملحقہ علاقوں پر مشتمل شمالی علاقہ جات کی آئینی حیثیت اس وقت قومی سیاسی حلقوں میں موضوع بحث ہے اور بعض حلقے مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ شمالی علاقہ جات کو پاکستان کا باقاعدہ آئینی حصہ قرار دے کر پانچویں صوبے کی حیثیت دی جائے، جبکہ دوسرے حلقوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ علاقہ تاریخی طور پر کشمیر کا حصہ ہیں اور مسئلہ کشمیر سے متعلقہ بین الاقوامی دستاویزات میں بھی شمالی علاقہ جات کو کشمیر کا حصہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے اس خطہ کو آئینی طور پر پاکستان کا صوبہ قرار دینے سے مسئلہ کشمیر کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچے گا۔ ان حلقوں کی تجویز یہ ہے کہ شمالی علاقہ جات کو آزادکشمیر کی اسمبلی اور حکومت میں نمائندگی دے کر آزاد کشمیر سپریم کورٹ و ہائیکورٹ کا دائرہ شمالی علاقہ جات تک وسیع کر دیا جائے تاکہ اس خطہ کے عوام کو سیاسی اور قانونی حقوق بھی حاصل ہو جائیں اور مسئلہ کشمیر کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ زیرنظر رسالہ میں اس نقطۂ نظر کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے جس کا مطالعہ موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے مفید ہو گا۔
’’مردِ مومن کا مقام اور ذمہ داریاں‘‘
از مولانا عبد القیوم حقانی
ناشر: مؤتمر المصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک پشاور
کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات ۳۶ قیمت ۵ روپے
زیرنظر رسالہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے فاضل استاذ اور معروف صاحبِ قلم مولانا عبد القیوم حقانی کی بعض تقاریر کا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے موجودہ دور میں ایک باشعور مسلمان کی ذمہ داریوں اور اسلامی نظام کے مختلف پہلوؤں کی افادیت و ضرورت پر بحث کی ہے۔ نئے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں اس رسالہ کی اشاعت و تقسیم بہت زیادہ مفید ہو گی۔
’’مقامِ نبوت کی عجمی تعبیر‘‘ کا تعاقب
افادات: استاذ العلماء مولانا عبد القیوم ہزاروی
ترتیب: مولانا حافظ عزیز الرحمٰن ایم اے ایل ایل بی
کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات ۸۰ قیمت ۱۲ روپے
ملنے کا پتہ: عبید اللہ انورؒ اکادمی، مین بازار، ٹیکسلا
حضراتِ صوفیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے جہاں احسان و سلوک کے میدان میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصہ کو اللہ رب العزت کے ذکر اور عبادت و مجاہدہ سے مانوس کر کے تزکیۂ نفس کی سنتِ نبویؐ کو ہر دور میں زندہ رکھا ہے وہاں فلسفہ و کلام کی جولانگاہ بھی ان کے رہوارِ فکر کے لیے غیرمانوس نہیں رہی اور انہوں نے وجودِ باری تعالیٰ اور تخلیقِ کائنات کے حوالہ سے ہونے والے فلسفیانہ مباحث کی سنگلاخ وادیوں میں بادہ پیمائی کر کے اسی زبان میں اسلامی عقائد کی جس کامیابی کے ساتھ تشریح کی ہے اس نے اسلامی عقائد کے خلاف مختلف حلقوں کی طرف سے ہونے والی فلسفیانہ یلغار کا رخ موڑ کر رکھ دیا ہے۔
حضرات صوفیائے کرام قدس اللہ اسرارہم نے فلسفہ کائنات پر بحث کے دوران مختلف فلسفیانہ مکاتبِ فکر کا سامنا کرتے ہوئے بعض مقامات پر انہی کی زبان اور اصطلاحات سے کام لیا اور متعدد نئی اصطلاحات بھی اختیار کی جو ان مباحث کو عام ذہنوں کے دائرہ میں لانے کے لیے ضروری تھیں۔ یہ اصطلاحات ان ذہنوں کے لیے اجنبی اور نامانوس ثابت ہوئیں جنہیں ان مباحث کی گہرائی اور اہمیت کا ادراک نہیں اور اور ظاہربین حضرات نے صوفیائے کرامؒ کی ان اصطلاحات کو موردِ طعن و اعتراض بنا لیا۔
گذشتہ دنوں جناب ابوالخیر اسدی نے ’’مقامِ نبوت کی عجمی تعبیر‘‘ کے نام سے ایک رسالہ میں یہی روش اختیار کی اور وحدت الوجود، حقیقت محمدیہ، نبوت ذاتی و عرضی اور قسم کے خالص علمی اور دقیق فلسفیانہ مباحث کے حوالہ سے برصغیر کے نامور متکلم، فلسفی اور صوفی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے بعض مضامین کو ہدفِ تنقید بنایا۔
زیرنظر رسالہ میں استاذ العلماء حضرت مولانا عبد القیوم ہزاروی مدظلہ العالی نے جناب اسدی کے ان اعتراضات کا علمی انداز میں جواب دے کر یہ واضح کیا ہے کہ مولانا نانوتویؒ اور دیگر صوفیاء کرامؒ پر اسدی صاحب اور اس قبیل کے دیگر حضرات کے اعتراضات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اہلِ علم کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ خاصی دلچسپی کا باعث ہو گا۔
’’اللہ کی رحمت کا خزانہ‘‘
مرتب: حافظ نذیر احمد نقشبندی
ناشر: حبیب کلاتھ ہاؤس، ۲۰ خاکوانی کلاتھ مارکیٹ، گوجرانوالہ
کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات ۱۹۲
یہ قرآن کریم کی گیارہ سورتوں، نماز کے فضائل، حج و عمرہ کے فضائل اور طریقہ، درود شریف کے فضائل اور ذکر کی فضیلت اور مختلف اوقات کی مسنون دعاؤں کا خوبصورت مجموعہ ہے جسے خانقاہ سراجیہ مجددیہ کندیاں کے خادم خصوصی جناب حافظ نذیر احمد نقشبندی مجددی نے مرتب کیا ہے اور جناب شیخ خورشید انور، جناب شیخ محمد یوسف اور ان کے دیگر برادران نے اپنے والدین اور ہمشیرہ مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے شائع کیا ہے جو مذکورہ بالا پتہ کے علاوہ انور برادرز، مین بازار، وزیر آباد سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
ذیابیطس کے اسباب اور علاج
حکیم محمد عمران مغل
ذیابیطس یعنی پیشاب میں شکر آنا، دمہ، فالج، جوڑوں کا درد، بواسیر خونی وغیرہ کے مریض آج کل کثرت سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ امراض پہلے بھی تھے مگر حیرانگی اس بات کی ہے کہ جدید دور میں ایک ایک پہلو پر سینکڑوں مفکرین اور ڈاکٹرز یا سائنس دان غوروفکر کر رہے ہیں مگر یہ امراض ؏ ’’مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی‘‘ کی عکاسی کر رہے ہیں۔
ذیابیطس اور بلڈپریشر پچھلی دہائی سے پاکستان میں تیزی سے پھیلے اور بجائے ختم ہونے کے اپنے ساتھ ایک اور عذاب ایڈز کی شکل میں لائے۔ ذیابیطس کا ذکر قدیم کتب میں نہایت پاکیزگی سے ملتا ہے۔ قدماء نے کیمیا عقل اور فکر کی خوردبین سے اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ اطباء قدیم کا یہ معینہ مسلک اور اسوہ حسنہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر مرض کے سبب کو تفصیل سے مخلوقِ خدا کے سامنے پیش کیا پھر علامات کو لکھ کر بال کی کھال تک اتاری۔ مثلاً شکر کیونکر خارج ہوتی ہے۔ قدماء نے غدد لعابیہ، بانقراس، جگر اور دماغ کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ غدد لعابیہ کا یہ فائدہ ہے کہ جو غذا کھائی جاتی ہے اس سے نشاستہ کے اجزاء میں تبدیل ہو کر شکر کی صورت اختیار کر کے جزوِ بدن بننے کے قابل ہوتی ہے جسے مالٹوز کہا جاتا ہے۔ پھر یہ نشاستہ معدے سے ہوتا ہوا انتڑیوں میں پہنچتا ہے وہاں بانقراس سے تین قسم کے خمیر ملتے ہیں جس سے یہ باریک ترین رگوں (عروق یا ساریقا) کے ذریعے جگر میں پہنچ کر ایک قسم کی شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے گلائی کوجن یا شکر انگوری کہتے ہیں۔
یہ شکر جگر میں جمع رہتی ہے اور بوقتِ ضرورت تھوڑی تھوڑی خون میں مل کر حرارت بدنی پیدا کرتی رہتی ہے۔ پھر اس شکر کا کچھ حصہ عضلات میں بھی موجود رہتا ہے مگر حرکت کی وجہ سے ایک گیس جسے کاربانک کہتے ہیں اور کچھ حصہ پانی کا بنتا ہے۔ اب پانی تو پسینہ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اور گیس تنفس کے ذریعے خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح شکر کا یہ فارمولا بھی ذہن میں آیا کہ یہ پانی اور کاربن کا مرکب ہے۔ چنانچہ شکر کو لوہے کے برتن میں گرم کریں تو اس کا پانی جل کر اڑ جائے گا اور کوئلہ کاربن کی شکل میں رہ جائے گا۔ یہی عمل ہمارے بدن میں قدرت نے بانقراس کے ذمہ لگا دیا۔ بانقراس سے جو رطوبت نکلتی ہے خون میں شامل ہو کر اس کا نظام ٹھیک رکھتی ہے۔
چنانچہ بانقراس یا اس سے نکلنے والی ہارمون میں خرابی ہو گئی تو شکر گردوں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی عمل شوگر کہلاتا ہے۔ اگر جگر کا عمل خرابی سے دوچار ہو جائے تو بھی شوگر کا مرض لاحق ہو گا کیونکہ شکر انگوری یعنی گلائی کوجن کو جگر اپنے اندر جمع رکھتا ہے، جب جگر کا عمل خراب ہوا تو شکر براہ راست پیشاب سے خارج ہونا شروع ہو گی۔ دماغ کا ایک خاص مقام ہے جسے طب کی زبان میں بطن چہارم کہتے ہیں، اگر سوئی چبھوئی جائے تو شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مقام کو شوگر پنکچر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام کا تعلق جگر کے ساتھ اعصاب کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ اس حصہ میں چوٹ بھی لگنے سے شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جگر کی رگیں کشادہ ہو کر جگر میں خون زیادہ پہنچتا ہے جس سے جگر اپنا کیمیائی عمل نہیں کر سکتا اور شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی جگر کلاہ گردہ یا امعا پر چوٹ لگ جائے تو بھی شکر آ جاتی ہے۔
اس کی پانچ بڑی علامات قدیم حکماء نے بیان فرمائی ہیں (۱) پیشاب کی کثرت (۲) شکر کا آنا (۳) پیاس کی شدت (۴) بھوک کی زیادتی (۵) جسم کا لاغر ہوتے جانا، اس کا انجام کارسل ہی ہوا کرتا ہے۔
غذا میں مواد شکریہ و نشاستہ موقوف کر دیں، ہر قسم کا گوشت خوب کھائیں۔ بقراط کا یہ زریں قول ہے کہ کسی عضو خاص کا استعمال اس عضو کو قوت بخشتا ہے چنانچہ ایلوپیتھی میں اسی اصول کے تحت انسولین کا انجکشن لگایا جاتا ہے جو بانقراس (لبلبہ) کے اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طبِ یونانی اور ایلوپیتھی دونوں طبیں افیون کے مرکبات پر متفق ہیں اس لیے افیون کا جوہر کوڈبن قابل تعریف خیال کیا جاتا ہے مگر طب یونانی میں اس کا بالکل معمولی استعمال بتایا گیا ہے۔ یہی حال جامن کا ہے۔ ہم تو عصاری جامن استعمال کرتے ہیں، اسی کو ڈاکٹر حضرات ایکسٹریکٹ جمیل لیکوئیڈ کی شکل میں مریض کے لیے اکسیر خیال کرتے ہیں۔ ڈایابین کا جزو اعظم یہی جامن ہی ہے۔
ذیل میں ایک نسخہ جو ہمہ صفت موصوف ہے، خلقِ خدا کی بہبود کے لیے پیشِ خدمت ہے، بنائیں اور مخلوقِ خدا کو فائدہ پہنچائیں۔
(۱) ھو الشافی ۔ گلو خشک، برگ جامن، خستہ جامن، اصل السوس مقشر، صمغ عربی، کتیرا، تخم نیلوفر، گاؤ زبان، گل سرخ، گل ارمنی، انار کے پھول، تخم خشخاش سفید، صندل سفید، کشتہ قلعی، کشتہ مرجان، مردارید تاسفۃ۔ یہ تمام ایک ایک تولہ۔ افیون خالص دو ماشہ، سب کو سفوف بنا کر چھ ماشہ خوراک صبح یا شام ہمراہ پانی کھائیں۔
(۲) اگر فی الحال پیشاب کی زیادتی ہے اور شوگر کی بیماری ابتدائی حالت میں ہے تو صرف حرمل کا سفوف بنا کر (یعنی اس کے بیج) صبح شام تین تین ماشہ دودھ سے کھائیں۔ فوری طور پر پیشاب رک کر شوگر کو بھی افاقہ ہو گا۔
(۳) نامی گرامی اطباء یہ بوٹیاں استعمال کا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جامن، گرٹا ربوٹی، کریلا، بیہڑے، ہلدی، شہتوت کے پتے اور بوٹی سدا بہار۔
والدین اور اولاد کے باہمی حقوق
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
بچوں کی مناسب نشوونما کے لیے تربیت و پرورش کی مناسب تدبیر والدین کا فرض ہے۔ ان کی جسمانی صحت کو درست رکھنے کے لیے مناسب کھیل اور تفریح کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور ان کو ایسے مواقع سے بچانا ضروری ہے جہاں مار پیٹ یا اعضاء کے ٹوٹنے اور ان کے ضائع ہونے کا غالب گمان یا وہمی احتمال بھی موجود ہو۔
پھر جب وہ سنِ تمیز کو پہنچ جائیں اور تعبیر پر قادر ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو فصیح و بلیغ زبان کی تعلیم دی جائے تاکہ ان کی زبان لکنت اور رکاوٹوں سے صاف ہو جائے۔ انہیں پاکیزہ اخلاق کا خوگر بنایا جائے اور ایسے آداب کی تعلیم دی جائے جو شرفاء اور سرداروں کے لیے مناسب ہیں۔ ذلت و مبانت اور تکبر و تعلّی دونوں کی افراطی و تفریطی طرفوں سے بچائے رکھیں۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بزرگوں کے سامنے گفتگو کے آداب و اخلاق سے ان کو آگاہ کریں۔
نصابِ تعلیم میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچوں کو ان علوم و فنون کی تعلیم دی جائے جو ان کے لیے معاش و معاد اور دین و دنیا دونوں میں فائدہ پہنچائیں۔
جب بچے حد بلوغ تک پہنچ جائیں تو ان کے دو حق والدین کے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے مناسب پیشے یا ہنر سکھائیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی شادی کرائیں۔
اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں اور ان کی تعظیم بجا لانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں۔ ان کی صوابدید پر عمل کریں اور کبھی ان کے سامنے اُف تک نہ کریں۔ حتی المقدور والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیئے۔
(البدور البازغۃ مترجم ۔ ص ۱۴۲)
سود کے خلاف قرآنِ کریم کا اعلانِ جنگ
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
قرآنِ کریم میں خلافتِ الٰہیہ کے قیام سے مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک ایسی قوت پیدا کی جائے جس سے اموال اور حکمت، علم و دانش دونوں کو لوگوں میں صرف کیا جائے اور پھیلایا جائے۔ اب سودی لین دین اس کے بالکل منافی اور مناقض ہے۔ قرآن کریم کی قائم کی ہوئی خلافت میں ربوٰ (سود) کا تعامل کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا جواز بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نور و ظلمت کا اجتماع۔ ربٰو سود خواروں کے نفوس میں ایک خاص قسم کی خباثت پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر یہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ’’اضعافًا مضاعفًا‘‘ (دوگنا چوگنا) نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں سود کی وجہ سے اقتصادیات میں جو فساد اور اخلاقِ فاضلہ کی تباہی اور بربادی اور فطرتِ انسانیہ میں بگاڑ اور لوگوں پر اقتصادی طور پر ضیق و تنگی پیدا ہوتی ہے، یہ اس قدر ظاہر باتیں ہیں جن کے بیان کی ضرورت نہیں۔ اس لیے قرآنِ عظیم نے سود کو روئے زمین سے مٹانے کا اعلان کیا ہے اور انسانیت کو اس کے لینے اور دینے والوں کے شر و ظلم سے چھڑانے کا اعلان کیا ہے۔
سب سے پہلے مواعظِ حسنہ کے ذریعے سودی کاروبار سے منع کیا ہے، اگر اس سے باز نہ آئیں اور متنبہ نہ ہوں تو ان کے ساتھ سخت لڑائی کا اعلان کیا ہے اور ایسے لوگوں کی سطح ارضی سے مٹانے کا چیلنج کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی اساسی تعلیم بڑے محکم طریق پر دی ہے، ربٰو سے منع کیا گیا ہے، سود خواروں کے خلاف اعلانِ جنگ کیا ہے، لیکن پوری طرح رشد و ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور اس کی مضرتوں کو پوری طرح کھول کر بیان کر دینے کے بعد۔ یقیناً یہ رشد و ہدایت کے منافی اور خلاف ہے، اب اس کے خلاف جنگ جبر و اکراہ نہیں ہو گا بلکہ عین انصاف کا تقاضا ہو گا۔
(الہام الرحمٰن)
جون ۱۹۹۰ء
شریعت بل اور شریعت کورٹ
قومی اسمبلی کی نازک ترین ذمہ داری
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
سینٹ آف پاکستان نے مولانا سمیع الحق اور مولانا قاضی عبد اللطیف کا پیش کردہ ’’شریعت بل‘‘ کم و بیش پانچ سال کی بحث و تمحیص کے بعد بالآخر متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ شریعت بل ۱۹۸۵ء میں پارلیمنٹ کے ایوانِ بالا کے سامنے رکھا گیا تھا، اسے عوامی رائے کے لیے مشتہر کرنے کے علاوہ سینٹ کی مختلف کمیٹیوں نے اس پر طویل غور و خوض کیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھی اسے بھجوایا گیا۔ شریعت بل کی حمایت اور مخالفت میں عوامی حلقوں میں گرما گرم بحث ہوئی، متعدد حلقوں کی طرف سے اس میں ترامیم پیش کی گئیں اور بالآخر ترامیم کے ساتھ شریعت بل کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔
اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نفاذ اسلام کی جدوجہد کے حوالہ سے ۱۹۴۹ء میں قرارداد مقاصد کی منظوری اور ۱۹۷۳ء میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیے جانے کے بعد یہ تیسرا اہم ترین واقعہ ہے۔ اول الذکر دو اقدامات کے ذریعے ملک کی نظریاتی اور اسلامی حیثیت کے تعین کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات و احکامات کو قومی پالیسیوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا تھا جبکہ شریعت بل ملک کے اجتماعی نظام میں اسلامی تعلیمات کے مطابق انقلابی عملی تبدیلیوں کا نقطۂ آغاز ہے۔
شریعت بل سینٹ سے منظور ہونے کے بعد اب قومی اسمبلی کے فلور پر آنے والا ہے اور اسے منظور کرنے کی ذمہ داری قومی اسمبلی کے ارکان کے لیے ایک کڑی آزمائش بن گئی ہے۔ ملک کے بعض حلقے اپنے گروہی مفادات اور مصلحتوں کی خاطر یقیناً شریعت بل کی منظوری میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے بلکہ ان کوششوں کا آغاز بھی ہوگیا ہے۔ لیکن قومی اسمبلی کے ارکان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ گروہی، جماعتی اور طبقاتی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر شریعت بل کے منظور شدہ مسودہ کا مطالعہ کریں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے ضمیر کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کریں کیونکہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی ایک مسلمان کے ایمان و عقیدہ کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے میدانِ حشر میں بارگاہِ ایزدی اور دربارِ مصطفویؐ میں جواب دہی کے مرحلہ سے بھی گزرنا ہوگا۔
نفاذ اسلام کے حوالہ سے شریعت بل کے علاوہ ایک اور اہم اور نازک مسئلہ بھی اس وقت قومی اسمبلی کے ارکان کے ضمیر کو دستک دے رہا ہے اور وہ ہے وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار سے مالیاتی امور کو مستثنٰی رکھنے کا مسئلہ جو اس وقت قومی حلقوں میں سنجیدگی کے ساتھ زیربحث ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کم و بیش دس سال قبل تشکیل دی گئی تھی اور اس کی ذمہ داریوں میں ملک میں رائج غیر اسلامی قوانین پر نظرثانی کا کام شامل تھا لیکن بعض دیگر قوانین کی طرح مالیاتی قوانین کو دس سال کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار سے مستثنٰی کر دیا گیا تھا۔ اور اس استثنا کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اس دوران متبادل مالیاتی نظام ترتیب پا جائے تاکہ موجودہ غیر اسلامی سودی مالیاتی نظام کو یکلخت ختم کرنے کی صورت میں کوئی خلا پیدا نہ ہو اور مالیاتی نظام افراتفری اور ابتری کا شکار نہ ہو جائے۔ دس سال کی یہ میعاد جون ۱۹۹۰ء کے دوران ختم ہو رہی ہے جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل ملکی اور بیرونی علماء اور ماہرین معیشت کی مشاورت اور راہنمائی سے سود سے پاک معاشی نظام کا مکمل خاکہ مرتب کر کے حکومت کے حوالے کر چکی ہے۔ لیکن حکومتی حلقوں کا یہ رجحان سامنے آرہا ہے کہ وہ وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار سے مالیاتی امور کو مستثنٰی رکھنے کی مدت میں مزید اضافہ کر کے موجودہ سودی نظام کو برقرار رکھنے کی فکر میں ہیں، اس مقصد کے لیے ارکانِ اسمبلی کو ہموار کرنے کی مہم جاری ہے اور یہ مسئلہ بھی قومی اسمبلی کے سامنے آنے والا ہے۔
قومی اسمبلی کے ارکان کے سامنے اس مسئلہ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ سود کو قرآن کریم نے صراحتاً حرام قرار دیا ہے بلکہ سود کے لین دین کو خدا اور رسولؐ کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ جبکہ موجودہ معاشی نظام کی بنیاد ہی سود پر ہے اور اسلام کے عملی نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے معاشی نظام کو سود اور اس جیسی خرابیوں سے یکسر پاک کر دیا جائے۔ اس لیے ہم قومی اسمبلی کے محترم ارکان سے گزارش کریں گے کہ وہ سود پر مبنی غیر اسلامی معیشت کو باقی رکھنے کی مہم کا ساتھ نہ دیں بلکہ اس بات پر زور دیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر سود سے پاک معاشی نظام کو ملک میں بلا تاخیر رائج کیا جائے۔
بہرحال شریعت بل اور شریعت کورٹ کے اختیارات کا مسئلہ ارکانِ اسمبلی کے ضمیر اور ایمان کے لیے چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اگر انہوں نے ان دو مسائل کے سلسلہ میں دین و ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار کا تعین کیا تو ان کا یہ عمل دنیا و آخرت میں ان کی نیک نامی اور سرخروئی کا باعث ہوگا، اور اگر وہ جماعتی مصلحتوں اور گروہی و طبقاتی مفادات کے حصار سے خود کو نہ نکال سکے تو سود پر اصرار اور شریعت کی بالادستی سے انحراف کے اس بدترین قومی جرم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی اور اخروی عذاب (العیاذ باللہ) کا سب سے پہلا اور بڑا ہدف وہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رسوائی اور ذلت سے پوری قوم کو پناہ میں رکھیں، آمین یا الٰہ العالمین۔
نفاذِ شریعت ایکٹ ۱۹۹۰ء
ادارہ
(سینٹ آف پاکستان نے مولانا سمیع الحق اور مولانا قاضی عبد اللطیف کا پیش کردہ ’’شریعت بل‘‘ پانچ سال کی طویل بحث و تمحیص کے بعد ۱۳ مئی ۱۹۹۰ء کو متفقہ طور پر ’’نفاذِ شریعت ایکٹ ۱۹۹۰ء‘‘ کے عنوان کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ یہ بل ۱۳ جولائی ۱۹۸۵ء کو ایوانِ بالا میں پیش کیا گیا تھا اور اس پر پانچ سال کے دوران متعدد کمیٹیوں نے کام کیا اور اسے سینٹ سیکرٹریٹ کی طرف سے عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے مشتہر بھی کیا گیا۔ بل میں مختلف حلقوں کی طرف سے متعدد ترامیم پیش کی گئیں اور ترامیم سمیت سینٹ نے بل کا جو آخری مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا ہے اس کا متن درج ذیل ہے۔ ادارہ)
ہرگاہ کہ قراردادِ مقاصد کو، جو پاکستان میں شریعت کو بالادستی عطا کرتی ہے، دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان ۱۹۷۳ء کے مستقل حصے کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔
اور ہر گاہ کہ مذکورہ قراردادِ مقاصد کے اغراض کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے فی الفور نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ لہٰذا حسبِ ذیل قانون بنایا جاتا ہے۔
(۱) مختصر عنوان، وسعت اور آغازِ نفاذ
(۱) یہ ایکٹ نفاذِ شریعت ایکٹ ۱۹۹۰ء کے نام سے موسوم ہو گا۔
(۲) یہ پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہو گا۔
(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہو گا۔
(۴) اس میں شامل کسی امر کا اطلاق غیر مسلموں کے شخصی قوانین پر نہیں ہو گا۔
(۲) تعریفات
اس ایکٹ میں، تاوقتیکہ متن سے اس سے مختلف مطلوب ہو، مندرجہ ذیل عبارات سے وہ مفہوم مراد ہے جو یہاں ترتیب وار دیا گیا ہے۔
(الف) ’’حکومت‘‘ سے مراد: (اول) کسی ایسے معاملے سے متعلق جسے دستور میں وفاقی قانون سازی کی فہرست یا مشترکہ قانون سازی کی فہرست میں شمار کیا گیا ہو، یا کسی ایسے معاملے کے بارے میں جس کا تعلق ’’وفاق‘‘ سے ہو ’’وفاقی حکومت‘‘ ہے، اور (دوم) کسی ایسے معاملے سے متعلق جسے مذکورہ فہرستوں میں سے کسی ایک میں شمار نہ کیا گیا ہو، یا کسی ایسے معاملے کے بارے میں جس کا تعلق صوبے سے ہو ’’صوبائی حکومت‘‘ ہے۔
(ب) شریعت کی تشریح و تفسیر کرتے وقت قرآن و سنت کی تشریح و تفسیر کے مسلّمہ اصول و قواعد کی پابندی کی جائے گی اور راہنمائی کے لیے اسلام کے مسلّمہ فقہاء کی تشریحات اور آراء کا لحاظ رکھا جائے گا جیسا کہ دستور کی دفعہ ۲۲۷ شق (۱) کی تشریح میں ذکر کیا گیا ہے۔
(ج) ’’عدالت‘‘ سے کسی عدالتِ عالیہ کے ماتحت کوئی عدالت مراد ہے۔ اس میں وہ ٹربیونل یا مقتدرہ شامل ہے جسے فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کی رو سے یا اس کے تحت قائم کیا گیا ہو۔
(د) ’’قراردادِ مقاصد‘‘ سے مراد وہ قراردادِ مقاصد ہے جس کا حوالہ دستور کے آرٹیکل ۲ (الف) میں دیا گیا ہے اور جس کو دستور کے ضمیمے میں درج کیا گیا ہے۔
(ز) ’’مقررہ‘‘ سے مراد اس ایکٹ کے تحت مقررہ قواعد ہیں۔
(د) ’’مستند دینی مدرسہ‘‘ سے مراد پاکستان یا بیرونِ پاکستان کا وہ دینی مدرسہ ہے جسے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یا حکومت قواعد کے مطابق تسلیم کرتی ہو۔
(ھ) ’’مفتی‘‘ سے مراد شریعت سے کماحقہ واقف وہ مسلمان عالم ہے جو کسی باقاعدہ دینی مدرسہ کا سند یافتہ اور تخصیص فی الفقہ کی سند حاصل کر چکا ہو اور پانچ سال کسی مستند دینی مدرسہ میں علومِ اسلامی کی تدریس یا افتاء کا تجربہ رکھتا ہو، یا دس سال تک کسی مستند دینی مدرسے میں علومِ اسلامی کی تدریس یا افتاء کا تجربہ رکھتا ہو، اور جسے اس قانون کے تحت شریعت کی تشریح اور تعبیر کرنے کے لیے عدالتِ عظمٰی، کسی عدالتِ عالیہ، یا وفاقی شرعی عدالت کی اعانت کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔
(۳) شریعت کی بالادستی
شریعت پاکستان کا اعلیٰ ترین قانون ہو گی اور اسے مذکورہ ذیل طریقے سے نافذ کیا جائے گا اور کسی دیگر قانون، رواج یا دستور العمل میں شامل کسی امر کے علی الرغم مؤثر ہو گی۔
(۴) عدالتیں شریعت کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں گی
(۱) اگر کسی عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا جائے کہ کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم شریعت کے منافی ہے تو عدالت، اگر اسے اطمینان ہو کہ سوال غور طلب ہے، ایسے معاملات کی نسبت، جو دستور کے تحت وفاقی شرعی عدالت کے اختیارِ سماعت کے اندر آتے ہوں، وفاقی شرعی عدالت سے استصواب کرے گی۔ اور مذکورہ عدالت مقدمہ کا ریکارڈ طلب کر سکے گی اور اس کا جائزہ لے سکے گی اور امرِ تنقیح طلب کا ساٹھ دن کے اندر اندر فیصلہ کرے گی۔
مگر شرط یہ ہے کہ اگر سوال کا تعلق کسی ایسے مسئلے سے ہو جو دستور کے تحت وفاقی شریعت کورٹ کے دائرۂ اختیار سے باہر ہو تو عدالت امرِ تنقیح طلب کو عدالتِ عالیہ کے حوالے کر دے گی جو اس کا ساٹھ دن کے اندر اندر فیصلہ کرے گی۔
مزید شرط یہ ہے کہ عدالت کسی ایسے قانون یا قانون کے حکم کی نسبت اس کے شریعت کے منافی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کسی سوال پر غور نہیں کرے گی جس کا وفاقی شرعی عدالت یا عدالتِ عظمٰی کی شرعی مرافعہ بینچ پہلے ہی جائزہ لے چکی ہو اور اس کے شریعت کے منافی نہ ہونے کا فیصلہ کر چکی ہو۔
(۲) ذیلی دفعہ (۱) کا دوسرا فقرہ شرطیہ وفاقی شرعی عدالت یا عدالتِ عظمٰی کی شرعی مرافعہ بینچ کی جانب سے دیے گئے کسی فیصلے یا صادر کسی حکم پر نظرثانی کرنے کے اختیار پر اثرانداز نہیں ہو گا۔
(۳) عدالتِ عالیہ خود اپنی تحریک پر، یا پاکستان کے کسی شہری، یا وفاقی حکومت، یا کسی صوبائی حکومت کی درخواست پر، یا ذیلی دفعہ (۱) کے پہلے فقرہ شرطیہ کے تحت، اس سے کیے گئے کسی استصواب پر اس سوال کا جائزہ لے سکے گی اور فیصلہ کر سکے گی کہ آیا کوئی مسلم شخصی قانون، کسی عدالت یا ٹربیونل کے ضابطۂ کار سے متعلق کوئی قانون، یا کوئی اور قانون جو وفاقی شرعی عدالت کے دائرۂ اختیار سے باہر ہو، یا مذکورہ قانون کا کوئی حکم، شریعت کے منافی ہے یا نہیں۔
مگر شرط یہ ہے کہ سوال کا جائزہ لیتے ہوئے عدالتِ عالیہ توضیح طلب سوال سے متعلقہ شعبہ کا تخصیصی ادراک رکھنے والے ماہرین میں سے، جن کو وہ مناسب سمجھے، طلب کرے گی اور ان کے نقطۂ نظر کی سماعت کرے گی۔
(۴) جبکہ عدالتِ عالیہ ذیلی دفعہ (۲) کے تحت کسی قانون یا قانون کے حکم کا جائزہ لینا شروع کرے اور اسے ایسا قانون یا قانون کا حکم شریعت کے منافی معلوم ہو، تو عدالتِ عالیہ
- ایسے قانون کی صورت میں جو دستور میں وفاقی فہرست قانون سازی یا مشترکہ فہرست قانون سازی میں شامل کسی معاملے سے متعلق ہو، وفاقی حکومت کو
- یا کسی ایسے معاملے سے متعلق کسی قانون کی صورت میں جو ان فہرستوں میں سے کسی ایک میں بھی شامل نہ ہو، صوبائی حکومت کو
ایک نوٹس دے گی جس میں ان خاص احکام کی صراحت ہو گی جو اسے بایں طور پر منافی معلوم ہوں، اور مذکورہ حکومت کو اپنا نقطۂ نظر عدالتِ عالیہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مناسب موقع دے گی۔
(۵) اگر عدالتِ عالیہ فیصلہ کرے کہ کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم شریعت کے منافی ہے تو وہ اپنے فیصلے میں حسبِ ذیل بیان کرے گی۔
(الف) اس کی مذکورہ رائے قائم کرنے کی وجوہ۔
(ب) وہ حد جہاں تک ایسا قانون یا حکم بایں طور پر منافی ہے، اور
(ج) اس تاریخ کا تعین جس پر وہ فیصلہ نافذ العمل ہو گا۔
مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ اس میعاد کے گزرنے سے پہلے، جس کے اندر عدالتِ عظمٰی میں اس کے خلاف اپیل داخل ہو سکتی ہو، یا جبکہ اپیل بایں طور پر داخل کر دی گئی ہو، اس اپیل کے فیصلے سے پہلے نافذ العمل نہیں ہو گا۔
(۶) عدالتِ عالیہ کو اس دفعہ کے تحت اپنے دیے ہوئے کسی فیصلے یا صادر کردہ کسی حکم پر نظرثانی کرنے کا اختیار ہو گا۔
(۷) اس دفعہ کی رو سے عدالتِ عالیہ کو عطا کردہ اختیارِ سماعت کو کم از کم تین ججوں کی کوئی بینچ استعمال کرے گی۔
(۸) اگر ذیلی دفعہ (۱) یا ذیلی دفعہ (۲) میں محولہ کوئی سوال عدالتِ عالیہ کی یک رکنی بینچ یا دو رکنی بینچ کے سامنے اٹھے تو اسے کم از کم تین ججوں کی بینچ کے حوالے کیا جائے گا۔
(۹) اس دفعہ کے تحت کسی کارروائی میں عدالتِ عالیہ کے قطعی فیصلے سے ناراض کوئی فریق مذکورہ فیصلے سے ساٹھ دن کے اندر عدالتِ عظمٰی میں اپیل داخل کر سکے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ وفاق یا کسی صوبے کی طرف سے اپیل مذکورہ فیصلے کے چھ ماہ کے اندر داخل کی جا سکے گی۔
(۱۰) اس قانون میں شامل کوئی امر یا اس کے تحت کوئی فیصلہ، اس قانون کے آغازِ نفاذ سے قبل کسی عدالت یا ٹربیونل یا مقتدرہ کی طرف سے کسی قانون کے تحت دی گئی سزاؤں، دیے گئے احکام یا سنائے ہوئے فیصلوں، منظور شدہ ڈگریوں، ذمہ کیے گئے واجبات، حاصل شدہ حقوق، کی گئی تشخیصات، وصول شدہ رقوم، یا اعلان کردہ قابلِ ادا رقوم پر اثر انداز نہیں ہو گا۔
تشریح: اس ذیلی دفعہ کی غرض کے لیے ’’عدالت‘‘ یا ’’ٹربیونل‘‘ سے مراد اس قانون کے آغازِ نفاذ سے قبل کسی وقت کسی قانون یا دستور کی رو سے یا اس کے تحت قائم شدہ کوئی عدالت یا ٹربیونل ہو گی۔ اور لفظ ’’مقتدرہ‘‘ سے مراد فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت قائم شدہ کوئی مقتدرہ ہو گی۔
(۱۱) کوئی عدالت یا ٹربیونل بشمول عدالتِ عالیہ کسی زیرسماعت یا اس قانون کے آغازِ نفاذ کے بعد شروع کی گئی کسی کارروائی کو محض اس بنا پر موقوف یا ملتوی نہیں کرے گی کہ یہ سوال — کہ آیا کوئی قانون یا قانون کا حکم شریعت کے منافی ہے یا نہیں — عدالتِ عالیہ یا وفاقی شرعی عدالت کے سپرد کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ عدالتِ عالیہ نے اس سوال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اور ایسی کارروائی جاری رہے گی اور اس میں امرِ دریافت طلب کا فیصلہ فی الوقت نافذ العمل قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ بشرطیکہ عدالتِ عالیہ ابتدائی سماعت کے بعد یہ فیصلہ نہ دے دے کہ زیرسماعت مقدمات کو عدالت کے فیصلے تک روک دیا جائے۔
(۵) شریعت کے خلاف احکامات دینے پر پابندی
انتظامیہ کا کوئی بھی فرد بشمول صدر مملکت، وزیراعظم اور وزیراعلیٰ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکے گا، اور اگر ایسا کوئی حکم دے دیا گیا ہو تو اسے عدالتِ عالیہ میں چیلنج کیا جا سکے گا۔
(۶) عدالتی عمل اور احتساب
حکومت کے تمام عمال دستور کے تابع رہتے ہوئے اسلامی نظامِ انصاف کے پابند ہوں گے اور شریعت کے مطابق عدالتی احتساب سے بالاتر نہیں ہوں گے۔
(۷) علماء کو جج اور معاونینِ عدالت مقرر کیا جا سکے گا
(۱) ایسے تجربہ کار اور مستند علماء جو اس قانون کے تحت مفتی مقرر کیے جانے کے اہل ہوں، عدالتوں کے ججوں اور معاونینِ عدالت کے طور پر مقرر کیے جانے کے بھی اہل ہوں گے۔
(۲) ایسے اشخاص جو پاکستان یا بیرون ملک اس مقصد کے لیے متعلقہ حکومت کے تسلیم شدہ اسلامی علوم کے معروف اداروں اور مستند دینی مدارس سے شریعت کا راسخ علم رکھتے ہوں، فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، شریعت کی تشریح اور تعبیر کے لیے عدالت کے سامنے اس مقصد کے لیے وضع کیے جانے والے قواعد کے مطابق پیش ہونے کے اہل ہوں گے۔
(۳) صدر، چیف جسٹس عدالتِ عالیہ کے مشورے سے ذیلی دفعہ (۱) کی غرض کے لیے قواعد مرتب کرے گا، جن میں ججوں اور عدالتوں میں معاونینِ عدالت کی حیثیت سے تقرر کے لیے مطلوبہ اہلیت اور تجربہ کی وضاحت ہو گی۔
(۴) ایسے اشخاص جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد یا کسی دیگر یونیورسٹی سے قانون اور شریعت میں گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں رکھتے ہوں، فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، اس غرض کے لیے حکومت کے وضع کردہ قواعد کے مطابق ایڈووکیٹ کی حیثیت سے اندراج کے اہل ہوں گے۔
(۵) اس دفعہ کے احکام کسی طور پر بھی قانون پیشہ اشخاص اور مجالسِ وکلاء سے متعلق قانون کے تحت اندراج شدہ وکلاء کے مختلف عدالتوں، ٹربیونلوں اور دیگر مقتدرات بشمول عدالتِ عظمٰی، کسی عدالتِ عالیہ، یا وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہونے کے حق پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔
(۸) مفتیوں کا تقرر
(۱) صدر، چیف جسٹس پاکستان یا چیف جسٹس وفاقی عدالت اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے مشورہ سے، جس طرح وہ مناسب تصور کرے، ایسے اور اتنے مفتیوں کا تقرر کرے گا جو عدالتِ عظمٰی، عدالتِ عالیہ، اور وفاقی شرعی عدالت کی شریعت کے احکام کی تعبیر و تشریح میں اعانت کے لیے مطلوب ہوں۔
(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مقرر کردہ کوئی مفتی صدر کی رضامندی کے دوران اپنے عہدہ پر فائز رہے گا اور اس کا عہدہ فی الوقت کسی نائب اٹارنی جنرل برائے پاکستان کے برابر ہو گا۔
(۳) مفتی کا یہ فرض ہو گا کہ وہ حکومت کو ایسے قانونی امور کے بارے میں، جن پر شریعت کی تشریح و تعبیر درکار ہو، مشورہ دے۔ اور ایسے دیگر فرائض انجام دے جو حکومت کی طرف سے اس کے سپرد یا اس کو تفویض کیے جائیں۔ اور اسے حق حاصل ہو گا کہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں عدالتِ عظمٰی اور عدالتِ عالیہ میں، جب کہ وہ اس قانون کے تحت اختیارِ سماعت استعمال کر رہی ہوں، اور وفاقی شرعی عدالت میں سماعت کے لیے پیش ہو۔
(۴) کوئی مفتی کسی فریق کی وکالت نہیں کرے گا بلکہ کارروائی سے متعلق اپنی دانست کے مطابق شریعت کے حکم بیان کرے گا، اس کی توضیح، تشریح و تعبیر کرے گا، اور شریعت کی تشریح کے بارے میں اپنا تحریری بیان عدالت میں پیش کرے گا۔
(۵) حکومتِ پاکستان کی وزارتِ قانون و انصاف مفتیوں کے بارے میں انتظامی امور کی ذمہ دار ہو گی۔
(۹) شریعت کی تدریس و تربیت
(۱) مملکت، اسلامی قانون کے مختلف شعبوں میں تعلیم و تربیت کے لیے مؤثر انتظامات کرے گی تاکہ شریعت کے مطابق نظامِ عدل کے لیے تربیت یافتہ افراد دستیاب ہو سکیں۔
(۲) مملکت، ماتحت عدلیہ کے ارکان کے لیے وفاقی جوڈیشنل اکادمی اسلام آباد اور اس طرح کے دیگر اداروں میں مسلّمہ مکاتبِ فکر کے فقہ اور اصولِ فقہ کی تدریس و تربیت، نیز باقاعدہ وقفوں سے تجدیدی پروگراموں کے انعقاد کے لیے مؤثر انتظامات کرے گی۔
(۳) مملکت، پاکستان کے لاء کالجوں میں مسلّمہ مکاتبِ فکر کے فقہ اور اصولِ فقہ کے جامع اسباق کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔
(۱۰) معیشت کو اسلامی بنانا
(۱) مملکت اس امر کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی کہ پاکستان کے معاشی نظام کی تعمیر اجتماعی عدل کے اسلامی معاشی اصولوں، اقدار اور ترجیحات کی بنیاد پر کی جائے۔ اور دولت کمانے کے ان تمام ذرائع پر پابندی ہو جو خلافِ شریعت ہیں۔
(۲) صدر، اس قانون کے آغازِ نفاذ کے ساٹھ دن کے اندر ایک مستقل کمیشن مقرر کرے گا جو ماہرینِ معاشیات، علماء اور منتخب نمائندگانِ پارلیمنٹ پر مشتمل ہو گا جن کو وہ موزوں تصور کرے، اور ان میں سے ایک کو اس کا چیئرمین مقرر کرے گا۔
(۳) کمیشن کے چیئرمین کو حسبِ ضرورت مشیر مقرر کرنے کا اختیار ہو گا۔
(۴) کمیشن کے کارہائے منصبی حسبِ ذیل ہوں گے:
(الف) معیشت کو اسلامی بنانے کے عمل کی نگرانی کرنا اور عدمِ تعمیل کے معاملات وفاقی حکومت کے علم میں لانا۔
(ب) کسی مالیاتی قانون، یا محصولات اور فیسوں کے عائد کرنے اور وصول کرنے سے متعلق کسی قانونی یا بنکاری اور بیمہ کے عمل اور طریقہ کار کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سفارش کرنا۔
(ج) دستور کے آرٹیکل ۳۸ کی روشنی میں عوام کی سماجی اور معاشی فلاح و بہبود کے حصول کے لیے پاکستان کے معاشی نظام میں تبدیلیوں کی سفارش کرنا، اور
(د) ایسے طریقے اور اقدامات تجویز کرنا جن میں ایسے موزوں متبادلات شامل ہوں جن کے ذریعے وہ نظامِ معیشت نافذ کیا جا سکے جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔
(۵) کمیشن کی سفارش پر مشتمل ایک جامع رپورٹ اس کے تقرر کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے اندر وفاقی حکومت کو پیش کی جائے گی اور اس کے بعد کمیشن حسبِ ضرورت وقتاً فوقتاً اپنی رپورٹیں پیش کرتا رہے گا، البتہ سال میں کم از کم ایک رپورٹ پیش کرنا لازمی ہو گا۔ کمیشن کی رپورٹ حکومت کو موصول ہونے کے ۳ ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے سامنے بحث کے لیے پیش کی جائے گی۔
(۶) کمیشن کو ہر لحاظ سے، جس طرح وہ مناسب تصور کرے، اپنی کارروائی کے انصرام اور اپنے طریقہ کار کے انضباط کا اختیار ہو گا۔
(۷) جملہ انتظامی مقتدرات، ادارے اور مقامی حکام کمیشن کی اعانت کریں گے۔
(۸) وزارتِ خزانہ حکومتِ پاکستان اس کمیشن سے متعلق انتظامی امور کی ذمہ دار ہو گی۔
(۱۱) ذرائع ابلاغِ عامہ اسلامی اقدار کو فروغ دیں گے
مملکت کی یہ ذمہ داری ہو گی کہ وہ ایسے مؤثر اقدام کرے جن کے ذریعے ذرائع ابلاغِ عامہ سے اسلامی اقدار کو فروغ ملے، نیز نشر و ابلاغ کے ہر ذریعہ سے خلافِ شریعت پروگرام، فحاشی اور منکرات کی اشاعت پر پابندی ہو گی۔
(۱۲) تعلیم کو اسلامی بنانا
(۱) مملکت اسلامی معاشرہ کی حیثیت سے جامع اور متوازن ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ پاکستان کے نظامِ تعلیم و تدریس کی اساس اسلامی اقدار پر ہو۔
(۲) صدر مملکت اس قانون کے آغازِ نفاذ سے ساٹھ دن کے اندر تعلیم اور ذرائع ابلاغ کو اسلامی سانچہ میں ڈھالنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کرے گا جو ماہرینِ تعلیم، ماہرینِ ابلاغِ عامہ، علماء اور منتخب نمائندگانِ پارلیمنٹ پر مشتمل ہو گا، جن کو وہ موزوں تصور کرے، اور ان میں سے ایک کو اس کا چیئرمین مقرر کرے گا۔
(۳) کمیشن کے چیئرمین کو حسبِ ضرورت مشیر مقرر کرنے کا اختیار ہو گا۔
(۴) کمیشن کے کارہائے منصبی یہ ہوں گی:
(الف) دفعہ ۱۱ اور اس دفعہ کی ذیلی دفعہ (۱) میں متذکرہ مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کے تعلیمی نظام اور ذرائع ابلاغ کا جائزہ لے اور اس بارے میں سفارشات پیش کرے۔
(ب) تعلیم اور ذرائع ابلاغ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے عمل کی نگرانی کرے اور عدمِ تعمیل کے معاملات وفاقی حکومت کے علم میں لائے۔
(۵) کمیشن کی سفارشات پر مشتمل ایک جامع رپورٹ اس کے تقرر کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے اندر وفاقی حکومت کو پیش کی جائے گی اور اس کے بعد کمیشن حسبِ ضرورت وقتاً فوقتاً اپنی رپورٹیں پیش کرتا رہے گا۔ البتہ سال میں کم از کم ایک رپورٹ پیش کرنا لازمی ہو گا۔ کمیشن کی رپورٹ حکومت کو موصول ہونے کے تین ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے سامنے بحث کے لیے پیش کی جائے گی۔
(۶) کمیشن کو ہر لحاظ سے، جس طرح وہ مناسب تصور کرے، اپنی کارروائی کے انصرام اور اپنے طریقہ کار کے انضباط کا اختیار ہو گا۔
(۷) جملہ انتظامی مقتدرات، ادارے اور مقامی حکام کمیشن کی اعانت کریں گے۔
(۸) وزارتِ تعلیم حکومتِ پاکستان اس کمیشن سے متعلق انتظامی امور کی ذمہ دار ہو گی۔
(۱۳) عمّالِ حکومت کے لیے شریعت کی پابندی
انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے تمام مسلمان ارکان کے لیے فرائضِ شریعت کی پابندی اور کبائر سے اجتناب لازم ہو گا۔
(۱۴) قوانین کی تعبیر شریعت کی روشنی میں کی جائے گی
اس قانون کی غرض کے لیے
(اول) قانونِ موضوعہ کی تشریح و تعبیر کرتے وقت، اگر ایک سے زیادہ تشریحات اور تعبیرات ممکن ہوں، تو عدالت کی طرف سے اس تشریح و تعبیر کو اختیار کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں اور فقہی قواعد و ضوابط اور اصولِ ترجیح کے مطابق ہو، اور
(دوم) جب کہ دو اور دو سے زیادہ تشریحات و تعبیرات مساوی طور پر ممکن ہوں تو عدالت کی طرف سے اس تشریح و تعبیر کو اختیار کیا جائے گا جو اسلامی احکام اور دستور میں بیان کردہ حکمتِ عملی کے اصولوں کو فروغ دے۔
(۱۵) بین الاقوامی مالی ذمہ داریوں کا تسلسل
اس قانون کے احکام یا اس کے تحت دیے گئے کسی فیصلے کے باوجود اس قانون کے نفاذ سے پہلے کسی قومی ادارے اور بیرونی ایجنسی کے درمیان عائد کردہ مالی ذمہ داریاں اور کیے گئے معاہدے مؤثر، لازم اور قابل عمل رہیں گے۔
تشریح: اس دفعہ میں ’’قومی ادارے‘‘ کے الفاظ میں وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت، کوئی قانونی کارپوریشن، کمپنی، ادارہ، تجارتی ادارہ اور پاکستان میں کوئی شخص شامل ہوں گے۔ اور ’’بیرونی ایجنسی‘‘ کے الفاظ میں کوئی بیرونی حکومت، کوئی بیرونی مالی ادارہ، بیرونی سرمایہ منڈی بشمول بینک، اور کوئی بھی قرض دینے والی بیرونی ایجنسی بشمول کسی شخص کے شامل ہوں گے۔
(۱۶) موجودہ ذمہ داریوں کی تکمیل
اس قانون میں شامل کوئی امر یا اس کے تحت کوئی دیا گیا فیصلہ کسی عائد کردہ مالی ذمہ داری کی باضابطگی پر اثر انداز نہیں ہو گا، بشمول ان ذمہ داریوں کے جو وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا کسی مالی یا قانونی کارپوریشن یا دیگر ادارے نے کسی دستاویزات کے تحت واجب کی ہوں یا اس کی طرف سے کی گئی ہوں، خواہ وہ معاہداتی ہوں یا بصورتِ دیگر ہوں، یا ادائیگی کے وعدے کے تحت ہوں۔ اور یہ تمام ذمہ داریاں، وعدے اور مالی پابندیاں قابلِ عمل، لازم اور مؤثر رہیں گی۔
(۱۷) قواعد
متعلقہ حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے اس قانون کی اغراض کی بجاآوری کے لیے وضع کر سکے گی۔
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی — رپورٹ، پروگرام، عزائم
ادارہ
گوجرانوالہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے نام سے پرائیویٹ اسلامی یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ جو کچھ عرصہ پہلے تک محض ایک خواب نظر آتا تھا اب جمعیۃ اہل السنۃ کے باہمت راہنماؤں کی مسلسل محنت اور تگ و دو کے نتیجہ میں زندہ حقیقت کا روپ اختیار کر رہا ہے اور ’’شاہ ولی اللہ یونیورسٹی‘‘ کے لیے نہ صرف جی ٹی روڈ پر گوجرانوالہ سے لاہور کی جانب اٹاوہ کے پاس دو سو ساٹھ کنال جگہ حاصل کر لی گئی ہے بلکہ اس پر تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ ساری زمین قیمتاً خریدی گئی ہے اور اب تک زمین کی خریداری اور دیگر تعمیری و انتظامی اخراجات پر چالیس لاکھ روپے کے قریب رقم خرچ ہو چکی ہے جو گوجرانوالہ کے مخیر مسلمانوں کے تعاون سے حاصل ہوئی ہے۔
پرائیویٹ اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا خیال سب سے پہلے جمعیۃ اہل السنۃ والجماعۃ گوجرانوالہ کے صدر الحاج میاں رفیق کے ذہن میں آیا جو شہر کے معروف صنعتکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ملک کے انتظامی اور عدالتی شعبوں میں اسلامی تعلیم و تربیت سے بہرہ ور افراد کلیدی عہدوں پر نہیں آئیں گے اس وقت تک نہ تو موجودہ نظام کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسلامی قوانین و اقدار کے نفاذ کی طرف کوئی عملی پیشرفت ممکن ہے، اس لیے ہمیں سکولوں، کالجوں اور دینی مدارس کے روایتی انداز سے ہٹ کر ایک ایسے نظامِ تعلیم کی بنیاد رکھنی چاہیئے جس کے ذریعے ایک طرف نئی نسل کو معیاری جدید تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے، اور دوسری طرف دینی مدارس کے فارغ التحصیل علماء کو جدید علوم اور ضروریات سے اس حد تک بہرہ ور کر دیا جائے کہ وہ ملک کے اجتماعی نظام میں بھی مؤثر طور پر شریک ہو سکیں۔
میاں صاحب نے آج سے پانچ سال قبل اپنے رفقاء کے سامنے یہ تجویز پیش کی جسے قبول کر لیا گیا۔ شہر کی بزرگ علمی شخصیات شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور مولانا صوفی عبد الحمید سواتی کے سامنے تجویز رکھی گئی، انہوں نے بھی اسے پسند کیا اور اپنے بھرپور تعاون اور سرپرستی کا یقین دلایا۔ یونیورسٹی کے لیے مختلف نام سامنے آئے اور برصغیر پاک و ہند کے عظیم مفکر شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے نام پر اس تعلیمی ادارہ کا نام ’’شاہ ولی اللہ یونیورسٹی‘‘ تجویز کر لیا گیا۔ اس کے لیے جی ٹی روڈ پر لاہور کی جانب قلعہ چند بائیپاس چوک سے دو فرلانگ آگے ریلوے لائن کے ساتھ اٹاوہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے بتدریج زمین خریدی گئی جو اب ساڑھے بتیس ایکڑ یعنی دو سو ساٹھ کنال ہو چکی ہے۔
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے تعلیمی نصاب اور نظام کی ترتیب کے لیے ممتاز علماء، وکلاء اور پروفیسر صاحبان پر مشتمل ’’تعلیمی کمیٹی‘‘ کام کر رہی ہے جس کے سربراہ مولانا زاہد الراشدی ہیں اور مولانا مفتی محمد عیسٰی، پروفیسر میاں محمد اکرم، پروفیسر غلام رسول عدیم، ڈاکٹر محمد اقبال لون، پروفیسر عبد الرحیم ریحانی، پروفیسر حافظ عبید اللہ عابد، قاری گلزار احمد قاسمی، مفتی فخر الدین عثمانی، ارشد میر ایڈووکیٹ اور میاں محمد عارف ایڈووکیٹ شامل ہیں۔ تعلیمی کمیٹی نے نظام اور نصاب کا جو خاکہ بنایا ہے اس کے مطابق مندرجہ ذیل شعبے رکھے گئے ہیں:
- تعلیمی کام کا آغاز کالج سے کیا جائے گا جس میں میٹرک پاس طلبہ لیے جائیں گے اور انہیں چار سال میں بی اے کا مروجہ نصاب پڑھایا جائے گا۔ اس نصاب میں عربی اور اسلامیات کا کورس ازسرنو مرتب کیا جائے گا اور تمام تر نظام اقامتی ہو گا یعنی طلبہ کو ۲۴ گھنٹے یونیورسٹی میں رہنا ہو گا۔ اس ضمن میں تعلیمی کمیٹی کا ہدف یہ ہے کہ طالب علم چار سال میں اچھے نمبروں کے ساتھ بی اے پاس کرنے کے علاوہ عربی اور اسلامیات میں اس قدر مہارت حاصل کر لے کہ قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ایسا تربیتی نظام رکھا جائے کہ وہ ایک سچا، با اخلاق اور با کردار مسلمان ثابت ہو۔
- دینی مدارس کے طلبہ کے لیے دو شعبے رکھے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل علماء میں سے جو عمر اور ذہانت کے مطلوبہ معیار پر پورے اترتے ہوں انہیں پانچ سالہ کورس کے ذریعے مقابلہ کے امتحان کے لیے تیار کیا جائے گا تاکہ وہ سول سوروسز میں جا سکیں۔ اور جو فضلاء اس معیار پر پورے نہ اترتے ہوں انہیں انگریزی، تاریخ، پبلک ڈیلنگ اور دوسری ضروریات پر مشتمل دو سالہ کورس کرا کے کسی ایک مضمون میں ایم اے کا امتحان دلایا جائے گا۔
- گریجویٹ طلبہ کے لیے مختلف مضامین میں ایم اے کے امتحان کی تیاری کا اہتمام کیا جائے گا۔
- فقہ، حدیث، تفسیر، تاریخ، ادب، عربی اور دیگر مضامین میں تخصص (سپیشلائزیشن) کی کلاسیں شروع کی جائیں گی۔
- تاجروں، وکلاء اور ملازمت پیشہ طبقات کے لیے ان کی سہولت کے مطابق خصوصی اسلامی کورسز کا اہتمام کیا جائے گا۔
- جب تک ’’شاہ ولی اللہ یونیورسٹی‘‘ کی اپنی اسناد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں ہو جاتیں اس وقت تک امتحانات مروجہ سسٹم کے مطابق بورڈ اور پنجاب یونیورسٹی کے ذریعے دلوائے جائیں گے اور اسناد منظور ہو جانے کے بعد نیا نظام وضع کیا جائے گا۔
یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے آرکیٹیکٹس کی معروف فرم ’’سلیم ایسوسی ایٹس قرطبہ چوک لاہور‘‘ کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا ہے اور فرم نے یونیورسٹی کا ماسٹر پلان مرتب کر دیا ہے جس کے مطابق ایک انتظامی بلاک، چھ تعلیمی بلاک، دو ہوسٹل، ایک مسجد، تین اسٹاف کالونیاں، دو آڈیٹوریم، ایک بڑی لائبریری اور دیگر ضروریات کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تمام تعلیمی بلاک دو منزلہ ہوں گے اور ہر بلاک میں اٹھارہ کلاس رومز اور اساتذہ کے پندرہ کمرے ہوں گے۔
اس وقت تک اٹاوہ ریلوے کراسنگ سے یونیورسٹی تک پختہ سڑک تعمیر ہو چکی ہے جس کے لیے ضلع کونسل کے چیئرمین رانا نذیر احمد ایم این اے نے خصوصی منظوری دی ہے اور آفس بلاک کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی ہے جس میں ایک آفس، ایک میٹنگ روم اور تعمیری سامان کے دو گودام شامل ہیں۔ جبکہ پہلے تعلیمی بلاک کی بنیادوں کی کھدائی مکمل ہونے کے بعد بھرائی کا کام جاری ہے۔ آرکیٹیکٹ کے بتائے ہوئے اندازے کے مطابق ایک بلاک پر کم و بیش ستر لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور ایک سال میں اس کی تعمیر مکمل ہو گی۔ جبکہ انتظامیہ کا پروگرام یہ ہے کہ سالِ رواں کے اختتام تک بلاک کی تعمیر مکمل کر کے جنوری ۱۹۹۱ء سے ایف اے کی کلاسوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا، ان شاء اللہ العزیز۔
انتظامیہ نے یونیورسٹی کے تمام اخراجات اصحابِ خیر کے تعاون سے پورے کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور بطور پالیسی یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ کسی قسم کی سرکاری گرانٹ حاصل نہیں کی جائے گی، البتہ نصاب کی بہتری اور اسناد کی منظوری جیسے ضروری امور کے لیے حکومتی محکموں کا تعاون حسب ضرورت حاصل کیا جائے گا۔
گوجرانوالہ کے اصحابِ خیر کی دلچسپی اور تعاون حوصلہ افزا ہے اور نہ صرف یہ کہ اب تک خرچ ہونے والے چالیس لاکھ روپے کی کم و بیش ساری رقم گوجرانوالہ کے اصحابِ خیر نے فراہم کی ہے بلکہ آئندہ سال کے بجٹ کے لیے رمضان المبارک کے دوران انتظامیہ کے سرکردہ حضرات نے شہر کا دورہ کیا تو گوجرانوالہ کے زندہ دل شہریوں نے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ مختلف حضرات نے تعلیمی بلاک میں اپنی طرف سے ایک ایک کمرہ بنانے کا وعدہ کیا ہے جبکہ کلاس روم کی تعمیر کا تخمینہ نوے ہزار روپے اور چھوٹے کمرہ کا تخمینہ پینتالیس ہزار روپے لگایا گیا ہے۔ بعض حلقوں نے یونیورسٹی میں مسجد کی تعمیر کا وعدہ کیا ہے جو آٹھ کنال کے رقبہ میں تعمیر کی جا رہی ہے اور بیشتر حضرات نے نقد فنڈ کی صورت میں معقول حصہ ڈالا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک بلاک کی تعمیر کے اخراجات میں سے نصف کا ٹارگٹ حاصل ہو چکا ہے اور بقیہ کے لیے مہم جاری ہے۔
یونیورسٹی کے انتظامات کے لیے ایک باقاعدہ ٹرسٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی تشکیل کے لیے مختلف ٹرسٹ اداروں کے قواعد و ضوابط حاصل کیے گئے ہیں جن کی روشنی میں ’’شاہ ولی اللہ یونیورسٹی ٹرسٹ‘‘ کے اصول اور قواعد و ضوابط مرتب کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ سالِ رواں کے اختتام تک ٹرسٹ کی باقاعدہ تشکیل مکمل ہو جائے گی۔
یونیورسٹی کا نظریاتی تعلق اہل السنۃ والجماعۃ سے ہے اور اس کے تمام مذہبی معاملات شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور ان کے عظیم علمی خاندان کی تعلیمات کی روشنی میں طے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی پر کسی فرقہ یا مذہبی مکتب فکر کی چھاپ نہیں ہو گی اور ’’شاہ ولی اللہ یونیورسٹی‘‘ فرقہ بندی کی مروجہ حدود سے بالاتر ہو کر قرآن و سنت، ائمہ اہل سنت اور خانوادۂ ولی اللّٰہی کی تعلیمات کی روشنی میں علمی اور دینی خدمت سرانجام دے گی۔
اس مہم میں جو حضرات پیش پیش ہیں ان میں سے مولانا زاہد الراشدی، الحاج میں محمد رفیق، میاں محمد عارف، بابو محمد شمیم، میر ریاض انجم، شیخ محمد یوسف وزیرآبادی، جناب ایس اے حمید، جناب عبد القادر پھلرواں، حاجی محمد رفیق، حاجی شیخ محمد صدیق، جناب علاء الدین، جناب شریف بیگ، میاں محمد اکرم، جناب محمد مشتاق، شیخ محمد اشرف، شیخ محمد ابراہیم طاہر، حاجی شیخ محمد یعقوب، شیخ شکیل احمد، پروفیسر غلام رسول عدیم، ڈاکٹر محمد اقبال لون، پروفیسر عبد الرحیم ریحانی اور حافظ عبید اللہ عابد بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ جبکہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور مولانا عبد الحمید سواتی بھرپور طریقے سے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ دونوں بزرگ کئی بار اٹاوہ تشریف لے جا چکے ہیں اور یونیورسٹی کے ابتدائی تعمیری کام کا آغاز بھی دونوں بزرگوں کی موجودگی میں ان کی دعاؤں کے ساتھ ہوا تھا۔ گذشتہ دنوں یونیورسٹی کے رفقاء کی ایک تقریب بھی شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر کی صدارت میں یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں منعقد ہو چکی ہے جس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث نے اس بات پر بطور خاص زور دیا کہ علماء کرام کے لیے انگریزی زبان اور جدید علوم سے واقفیت ازحد ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے دورۂ برطانیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے وہاں جا کر اس کا احساس ہوا کہ اگر میں انگریزی زبان سے واقف ہوتا تو کہیں بہتر طریقہ سے اسلام کی خدمت کر سکتا تھا۔
شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے سائٹ آفس کے افتتاح کے موقع پر مکہ مکرمہ کے ممتاز عالم دین اور حرم پاک کے مدرس فضیلۃ الشیخ مولانا محمد مکی حجازی بھی تشریف لائے تھے اور دعا کے ساتھ یونیورسٹی کے سائٹ آفس کا افتتاح کیا تھا۔ اس موقع پر مولانا محمد مکی حجازی نے اس عظیم تعلیمی منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام کے ایک عظیم مجدد اور مصلح امام ولی اللہ دہلویؒ سے منسوب یہ تعلیمی ادارہ ملتِ اسلامیہ میں ایک نئے فکری اور علمی انقلاب کا ذریعہ بنے گا۔
جمعیۃ اہل السنۃ کے سیکرٹری جنرل شیخ محمد اشرف نے ایک ملاقات میں یہ تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ امام کعبہ فضیلۃ الشیخ عبد اللہ السبیل مدظلہ تشریف لائیں اور اپنے دستِ مبارک سے یونیورسٹی کے کسی تعلیمی بلاک کا سنگِ بنیاد رکھیں۔ ان سے ہمارا رابطہ قائم ہے اور ان شاء اللہ العزیز بہت جلد ہم ان کی تشریف آوری پر میزبانی کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ صدر انتظامیہ الحاج میاں محمد رفیق اور سیکرٹری جنرل شیخ محمد اشرف نے شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے لیے زمین کی خریداری اور تعمیری اخراجات کے سلسلہ میں حوصلہ افزا تعاون پر گوجرانوالہ کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تعاون کی رفتار میں اور اضافہ کریں اور مزید جوش و خروش کے ساتھ اس مہم میں شریک ہوں تاکہ ہم پروگرام کے مطابق پہلے تعلیمی بلاک کی تعمیر مکمل کر کے جنوری ۱۹۹۱ء سے ایف اے کی کلاسوں کا آغاز کر سکیں۔
امام المحدثین والفقہاء حضرت مولانا ابوحنیفہ نعمان بن ثابتؒ
الاستاذ محمد امین درانی
امام صاحبؒ کے پوتے عمر بن حماد بن ابی حنیفہؒ کے قول کے مطابق امام صاحبؒ کا نسب یوں ہے: ابوحنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی۔ زوطی اہلِ کابل سے تھے۔ انہوں نے کابل سے کوفہ ہجرت کی اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان کے والد بزرگوار ’’ثابتؒ‘‘ پیدائشی مسلمان تھے۔ ثابتؒ کی ملاقات حضرت علی بن ابی طالبؓ سے کوفہ میں ہوئی تھی جب ثابتؓ کو ان کے والد زوطیؒ حضرت علیؓ کی خدمت میں لے گئے تھے، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔
دوسری روایت آپ کے دوسرے پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ سے ہے۔ ان کے قول کے مطابق امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت بن نعمان بن المدزبان ہیں اور وہ فارس (ایران) کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے ان کے دادا نے کوفہ ہجرت کی اور وہیں آباد ہوئے۔ (اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ للصمیری)
ان دونوں اقوال میں تطبیق ایسی ہے کہ ’’زوطی‘‘ نعمان بن المدزبان کا لقب ہے۔ اس زمانے میں کابل پر اہلِ فارس حکمران تھے۔ کابل، فارس (ایران) کا محکوم علاقہ تھا تو کابل کو فارس میں شمار کر لیا گیا۔
ولادت
اکثر ائمہ سیرت و تاریخ کے اقوال کے مطابق امام ابوحنیفہ ۸۰ھ کو کوفہ میں پیدا ہوئے۔ صرف ائمہ حدیث میں محدث الحسن الخلال نے مشہور محدث زواد بن علیہ سے روایت کی کہ امام ابوحنیفہ ۶۱ھ کو پیدا ہوئے اور ۱۵۰ھ کو وفات پائی۔ تاریخِ وفات میں کوئی اختلاف نہیں سب کے نزدیک ۱۵۰ھ ہے، جس سال امام شافعیؒ کی ولادت ہوئی (مقدمہ جامع المسانید ص ۲۱ ۔۔۔) دونوں روایتوں کے مطابق وہ قرنِ اول کے آخر میں پیدا ہوئے جو صحابہ کرامؓ کا زمانہ ہے۔ انہوں نے تدریسِ اسلام (تدریسِ حدیث و فقہ) قرنِ ثانی (دوسری صدی) میں کی جو تابعینؒ کی صدی ہے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی تینوں صدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدیاں (خیر القرون) فرمایا اور ان لوگوں کی افضلیت اور عدالت کی شہادت دی جو ان تینوں صدیوں میں ہوں۔
صحابہؓ سے ملاقات
امام ابوحنیفہؒ کے حاسدوں نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ آپؒ کے زمانے میں چار صحابہؓ موجود تھے۔ انس ؓ بن مالک بصرہ میں، عبد اللہ ؓ بن ابی کوفہ میں، سہلؓ بن سعد مدینہ منورہ میں، اور عامر بن واثلہؓ مکہ میں، اور کسی سے نہیں ملے۔ تابعینؒ سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ تبع تابعین میں سے ہیں (تاریخ امام ابو زہرۃ مصری) (آخر مشکوٰۃ)
مذکورہ بالا روایت غلط ہے اور اس کے مقابلے میں امام ذہبی نے الخطیب سے بحوالہ تاریخ بغداد نقل کیا ہے کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بصرہ میں ملے اور ان سے احادیث کی روایت کی۔ امام الصمیری نے (اخبار ابی حنیفہ ص ۴۰ میں) لکھا ہے، جب امام صاحبؒ پندرہ سال کے ہوئے تو آپ نے انس ؓ بن مالک کو بصرہ میں دیکھا اور ان سے روایت کی۔ ابوداؤد الطیالسیؒ نے امام ابوحنیفہؒ سے روایت کی، ابوحنیفہؒ نے فرمایا میں ۸۰ھ کو پیدا ہوا، صحابی رسول عبد اللہ بن انیس کوفہ آئے (۹۴ھ) اور میں چودہ سال کا تھا کہ میں نے ان سے یہ حدیث لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ’’حبک الشیئ یعص و یعصم‘‘ (کسی چیز کی محبت آپ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے)۔ (ص ۲۳ مقدمہ جامع المسانید)
بشر بن الولید قاضی نے امام ابو یوسفؒ سے روایت کی کہ مجھے امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا، میں سولہ سال کا تھا اور حج کے لیے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گیا اور مسجد الحرام میں صحابیٔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن الحارث بن جزی الزبیدی کے حلقۂ درس میں بیٹھا اور ان سے یہ حدیث سنی ’’من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ھمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب‘‘ جو اللہ کے دین میں مہارت حاصل کریں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جو اس کے گمان میں نہ ہو۔
ایسے اور کئی واقعات سیرۃ و تاریخ و اسماء الرجال میں اس حقیقت کی شہادت کرتے ہیں کہ مشکوۃ المصابیح کے اسماء الرجال کے آخرمیں یا ابو زہرہؒ وغیرہ نے جو لکھا ہے وہ غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ تابعی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرامؓ کو دیکھا ان سے روایت کی۔ اس حقیقت کی تائید امام ابویوسفؒ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب امام ابوحنیفہؒ کے استاد حماد بن ابی سلیمانؒ نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت انس ؓ بن مالک کا یہی فتوٰی ہے کہ سجدۂ سہو سلام کے بعد ادا کرنا ہے۔ اس تحقیق کے لیے امام صاحب بصرہ تشریف لے گئے اور ان سے خود ہی مسئلہ سنا (اخبار ابی حنیفہ للصمیری ص ۵)۔
ہناد بن سری محدث نے امام ابوحنیفہ کی روایت واثلہ بن الاسقع صحابیؓ سے نقل کی اور محدث یحیٰی بن معین نے ابوحنیفہ کی روایت عائشہ بنت عجرو صحابیہؓ سے نقل کی۔ یہ ساری روایات صحیح ہیں اور ان روایات سے یہ حقیقت بخوبی عیاں ہوئی کہ امام ابوحنیفہؒ یقیناً تابعی ہیں۔
ابتدائی تعلیم
امام ابوحنیفہؒ نے قرآن مجید مشہور قاری امام القراءت عاصم بن ابی النجود الکوفی سے حفظ کیا۔ یہ بچپن کا زمانہ تھا۔ امام عاصمؒ نے خود اس کی شہادت کی۔ ’’اتیتنا صغیرًا و اتیناک کبیرًا‘‘ آپ ہمارے پاس چھوٹے آتے تھے اور ہم آپ کے پاس آپ کے بڑے ہونے پر آئے۔ امام عاصمؒ نے اپنے شاگرد ابوحنیفہؒ سے بعد میں احادیث اور فقہی مسائل کی روایت کی۔ امام عاصمؒ مشہور قاری حفصؒ کے استاد ہیں جن کی قراءت کی روایت سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ (ص ۳۰ س ۳ مقدمہ جامع المسانید)
تعلیمِ حدیث و فقہ
امام ابوحنیفہؒ نے چار ہزار ائمہ شیوخ التابعین سے حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اکثر حصۂ احادیث اپنے مشہور استاد حماد بن ابی سلیمانؒ سے روایت کی جو مدرسۂ کوفہ کے شیخ الحدیث تھے۔
ربیع بن یونس نے روایت کی کہ امام ابوحنیفہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کی خدمت میں گئے، عیسٰی بن موسٰی نے خلیفہ منصور سے کہا کہ آج ابوحنیفہ دنیا کا عالم ہے۔ خلیفہ منصور نے پوچھا، اے نعمان! آپ نے کن سے علم کیا؟ امام نے فرمایا عمرؓ بن الخطاب، علیؓ بن ابی طالب، عبد اللہؓ بن مسعود، اور عبد اللہؓ بن عباسؓ کے ساتھیوں سے علم حاصل کیا۔ عبد اللہ بن عباسؓ اپنے وقت کےبڑے عالم تھے (وہ خلیفہ منصور کے اجداد میں سے ہیں) خلیفہ منصور نے کہا، آپ معتمد انسان ہیں آپ پر (دین میں) بھروسہ کیا جا سکتا ہے‘‘۔ (مقدمہ جامع المسانید ص ۳۰ و ص ۳۱)
تدریس
امام حمادؒ بن ابی سلیمان کی وفات کے بعد علماء عراق کے بے حد اصرار پر امام ابوحنیفہؒ نے مدرسہ کوفہ میں احادیث کی تدریس شروع کی اور قرآن و سنت سے مستنبط فقہی احکام کی تعلیم دی۔ جلیل القدر تابعین آپ سے دینی مسائل میں فتوٰی لیتے تھے اور آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے امام ابوحنیفہؒ سے احادیث روایت کیں جن میں چند مشہور محدثین درج ذیل ہیں: (۱) عمرو بن دینار (۲) عبد اللہ بن المبارک (۳) داود الطائی (۴) یزید بن ہارون (۵) عباد بن العوام (۶) محمد بن الحسن الشیبانی (۷) ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری (۸) وکیع بن الجراح (۹) ہمام بن خالد (۱۰) سفیان بن عتیبہ (۱۱) فضیل بن عیاض (۱۲) سفیان الثوری (۱۳) ابن ابی لیلی (۱۴) ابن شبرمد (۱۵) قاری حمزہ بن حبیب (۱۶) آپ کے استاد امام القراء عاصم بن ابی النجود (۱۷) امام القراء نافع بن عبد الرحمٰن المدنی جو امام مالکؒ کے استاد ہیں (۱۸) اکیلے قاری عبد اللہ بن یزید نے امام ابوحنیفہ سے نو سو احادیث کی روایت کی۔ (ص ۲۹ جامع المسانید)۔امام شافعیؒ، امام احمدؒ بن حنبل، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ اوردیگر ائمہؒ حدیث نے آپ کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں سے روایت کی۰
اتنی تعداد میں جلیل القدر ائمہ حدیث کی روایت امام ابوحنیفہؒ سے اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نہ صرف فقیہ بلکہ امام المحدثین ہیں اور علمِ حدیث کے متبحر اور مستند اماموں میں سے ہیں۔ اور آپ کی کتبِ حدیث، احادیث کی ۱۵ مسندیں مع کتاب الاثار، جو امام محمد اور امام ابویوسف کی الگ کتابیں ہیں، دین کی اصحب کتب ہیں اور ان کا درجہ ان کتب حدیث سے اونچا ہے جو امام ابوحنیفہؒ کے بعد مرتب ہوئیں کیونکہ یہ روایات یا تو معتمد جلیل القدر تابعین سے ہیں یا براہِ راست اصحابؓ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ جو دوسری کتب حدیث کے رواۃ (جو غیر تابعین اور غیر صحابہ) ہیں ان سے زیادہ معتمد زیادہ افضل اور زیادہ ثقات ہیں اور ازراہِ انصاف اس حقیقت کے مطابق قران مجید کے بعد امام ابوحنیفہؒ کی کتب حدیث اصح الکتب ہیں۔ (امام بخاریؒ گیارہویں طبقہ کے محدث ہیں جبکہ امام ابوحنیفہؒ چھٹے طبقہ کے محدث ہیں)۔اور مقدمہ ابن خلدون کے ص ۳۸۸ پر جو درج ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے سترہ احادیث روایت کی ہیں یہ امام ابوحنیفہؒ کے حاسدوں کی ترجمانی ہے اور غلط بیانی کی انتہا ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی کے اقوال جو امام ابوحنیفہؒ کے خلاف ہیں وہ تعصب پر مبنی ہیں۔
علمی مجلسِ شورٰی
امام ابوحنیفہؒ نے ہزاروں شاگردوں میں سے چالیس ائمہ منتخب کیے جو مجتہدین تھے، ان کو علمی مجلسِ شورٰی کا ممبر بنایا جس کے سیکرٹری امام ابو یوسف تھے۔ امام ابوحنیفہؒ دینی مسئلہ اس مجلس میں پیش کرتے اور اپنے ان مجتہد ائمہ شاگردوں سے وہ احادیث اور آثار سنتے تھے، اور ایک ایک مہینہ اکثر اوقات مذاکرات طویل ہوتے تھے تب ہی کوئی بات تحقیق سے ثابت ہوتی تو امام ابو یوسفؒ اس کو درج کرتے تھے۔ دینی مسائل کی تحقیق کے لیے مجلسِ شورٰی کی تاسیس امام ابوحنیفہؒ کا ایک منفرد عمل ہے جو باقی ائمہ کرامؒ کو نصیب نہیں ہوا۔ امام ابوحنیفہؒ کہا کرتے تھے لوگوں نے مجھے دوزخ کے اوپر پل بنا دیا ہے، سارا بوجھ میرے اوپر ہے، اس لیے میرے ساتھیو! میری مدد کرو۔
امام ابوحنیفہؒ بشر ہیں، اگر کبھی خطا ہو جاتی تو یہ ائمہ کبار ان کو احادیث و آثار سنا کر حق کی طرف واپس کرتے۔ انہوں نے امام ابو یوسفؒ سے کہا، کوئی بات بغیر تحقیق درج نہ کریں، بغیر تحقیق والی بات اگر آج ہے تو کل اسے چھوڑ دوں گا اور اس سے رجوع کروں گا۔ یہ حقیقت اس بات کی شاہد ہے کہ حنفی مسائل اجماعی اور سو فیصد صحیح ہیں۔
مذہب حنفی کی تاسیس
کوفہ عراق کا اہم ترین شہر ہے۔ عراق کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمرؓ بن الخطاب خلیفۂ دوم نے صحابہ کرامؓ میں سے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو کوفہ میں تعلیم و تدریس اور قضاء کے لیے منتخب فرمایا اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اس وقت دینِ اسلام کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور مدینہ منورہ میں وصالِ نبویؐ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر اور حضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ تمام احکام آپ کے سامنے نازل ہوئے۔ ناسخ و منسوخ کا علم سب سے زیادہ آپؓ کو ہوا کیونکہ باقی اصحابِ رسول کوئی نہ کوئی کام یا کاروبار کرتے تھے جبکہ عبد اللہ بن مسعودؓ کا پیشہ صرف خدمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے وہ دین کے بہت بڑے عالم اور فقیہ بنے اور اس خوبی کے تحت حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کو مدرسہ کوفہ کا پہلا معلم مقرر فرمایا۔ عہدِ فاروقی میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کوفہ میں درس دیا کرتے تھے۔ عہدِ عثمانی میں مدینہ منورہ میں عبد اللہ بن مسعودٌ کی کمی محسوس کی گئی تو خلیفہ سومؓ نےآپ کو وہاں بلایا، پھر مسجد نبویؐ میں درس دیتے رہے اور وفات کے بعد جنت البقیع میں دفن ہوئے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے بعد آپ کے شاگردوں حضرت علقمہ نخعی، مسروق الہمدانی، ابی قاضی شریح، اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں ابراہیم النخعی، عامر الشعبی، حاد بن ابی سلیمان، پھر ان کے شاگرد امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہم نے عبد اللہ بن مسعودؓ کی وہ اسلامی تعلیم لوگوں کو سکھائی جو اس جلیل القدر صحابیؓ نے اپنی ساری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی تھی۔ اور یہی اسلامی تعلیم مذہب حنفی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مذہب حنفی کوئی نیا مذہب نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
امام ابوحنیفہؒ، عبد اللہ بن مسعودؓ کے قائم کردہ مدرسے میں تدریسِ حدیث اور فقہ کیا کرتے تھے اور اس علمی خدمت کے ساتھ آپ اونی اور ریشمی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور تجارت کا منافع اپنے شاگردوں اور دیگر محتاجوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ نے تدریسِ اسلام پر کوئی اجر نہیں لیا۔ امام ابوحنیفہؒ نے جن چالیس اماموں کو تدوینِ فقہ اسلامی کے لیے منتخب کیا تھا ان میں سے چار امامؒ بہت مشہور ہوئے۔
(۱) امام بو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاریؒ
(ولادت ۱۱۳ھ وفات ۱۸۲ھ) جن کی مشہور کتاب ’’مسائل الخراج‘‘ ہے جس میں اسلامی ٹیکس، صدقات اور مالی مسائل مذکور ہیں۔ انہوں نے امام ابوحنیفہؒ سے کتاب الآثار اور مسند فی الحدیث کی روایت کی۔امام شافعیؒ کی کتاب الأم کی آخیر ساتویں جلد ص ۸۷ سے ص ۱۵۰ تک امام ابو یوسفؒ کے علمی اقوال درج ہیں۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ انتہائی غریب و نادار تھے اور حدیث و فقہ کے شیدائی تھے۔ ان کے والد ابراہیم الانصاریؒ نے آپ سے کہا ابو حنیفہؒ کی روٹی مرغن ہے اور آپ کو مزدوری کی ضرورت ہے، اس لیے والد کی اطاعت کی خاطر ابوحنیفہؒ کے درس سے چند روز غیر حاضر رہے۔ جب حاضر ہوئے ان سے پوچھا کیوں غیر حاضری کی؟ امام ابویوسفؒ کے بتانے پر سبق کے آخیر میں آپ کو اشارہ کر کے سو درہم کی تھیلی دی اور حاضری کی تلقین کی۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سو درہم دیے اور وقفہ وقفہ سے امام ابوحنیفہؒ آپ کو سو سو درہم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام ابو یوسفؒ غنی اور مالدار ہوئے (ص ۹۲ اخبار ابی حنیفہ للصمیری)۔
امام ابو یوسفؒ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی مجلس امام ابوحنیفہؒ اور امام ابن لیلیؒ کی مجلسوں سے مجھے زیادہ پسند نہ تھی۔ میں نے ابوحنیفہؒ سے بڑا فقیہ اور ابن ابی لیلی سے بڑا قاضی نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا، میں امام ابوحنیفہؒ کی صحبت میں سترہ سال رہا، میں نہ عید الفطر اور نہ عید الاضحٰی میں ان سے غیر حاضر رہا سوائے اس صورت میں جبکہ میں بیمار تھا۔ آپ فرماتے تھے ہر نماز اور ہر عبادت کے بعد امام ابوحنیفہؒ کے لیے دعا کرتا رہتا۔ امام حماد بن ابی حنیفہ (امام الاعظم) فرماتے ہیں کہ میرے والد (امام ابوحنیفہؒ) کے دائیں طرف امام ابو یوسفؒ اور بائیں جانب امام زفرؒ تھے۔ مسائل میں ہر ایک دوسرے کے خلاف دلائل پیش کرتے رہے۔ صبح سے ظہر تک دونوں کا مناظرہ جاری تھا، جب ظہر کے لیے مؤذن نے اذان دی امام ابوحنیفہؒ نے اپنا ہاتھ امام زفرؒ کی ران پر مارا اور فرمایا اس شہر میں سربراہی کی امید نہ کر جہاں ابو یوسف موجود ہو۔ امام ابوحنیفہؒ نے امام زفرؒ کے خلاف امام ابو یوسفؒ کے حق میں فیصلہ دیا (اخبار ابی حنیفہ للصمیری ص ۹۵)۔
امام ابو جعفرؒ طحاویؒ نے فرمایا میں نے ۔۔۔۔۔۔۔۔ محدث علی بن الجعدؒ نے فرمایا، امام ابو یوسفؒ نے ہمیں حدیث کی روایت کی۔ اس وقت لوگوں سے مجلس بھری ہوئی تھی، ایک آدمی نے پوچھا اے ابوالحسن (ابن ابی عمران) کیا آپ کو ابو یوسفؒ یاد ہیں؟ تو محدث علی بن الجعدؒ نے فرمایا جب آپ ابو یوسفؒ کا نام لیتے ہیں تو پہلے اشنان اور گرم پانی سے منہ دھو لیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں نے ابو یوسف کی طرح کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ابن ابی عمرانؒ فرماتے ہیں کہ محدث علی بن الجعدؒ نے سفیان ثوری، حسن بن صالح، امام مالک، ابن ابی ذیب، لیث بن سعد اور شعبہ بن الحجاج جیسے اماموں رحمۃ اللہ علیہم کو دیکھا تھا، وہ سب پر ابو یوسفؒ کو ترجیح دیتے تھے (اخبار ابی حنیفہ ص ۹۶)
(۲) امام زفر بن الہذیذ بن قیس العنبریؒ
امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد امام حسن بن زیاد الؤلؤی نے فرمایا کہ امام اعظمؒ کے دو شاگرد امام زفرؒ اور امام داود طائی گہرے دوست تھے۔ امام داود طائی نے عبادت کی طرف زیادہ توجہ دی جبکہ امام زفرؒ نے فقہ اور عبادت دونوں کی طرف زیادہ توجہ دی۔ امام زفرؒ امام ابوحنیفہؒ کے جوتوں قریب بیٹھتے تھے جبکہ امام ابو یوسفؒ آپؒ کے دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے۔ امام وکیع بن الجراحؒ، جو امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد اور امام شافعیؒ کے استاد ہیں، فرمایا کرتے تھے امام زفرؒ انتہائی پرہیزگار تھے، ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔
امام محمد بن وہبؒ فرماتے ہیں کہ امام زفرؒ ابوحنیفہؒ کے ان دس اکابر شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی نگرانی میں کتابیں تالیف کیں۔ اہلِ بصرہ کے علماء امام ابوحنیفہؒ کے تابع اس لیے ہوئے کہ بصرہ کے لوگ امام زفرؒ کے علم سے متاثر ہوئے اور آپ کے علم کو پسند کیا۔ امام زفرؒ نے فرمایا، میں نے یہ علم امام ابوحنیفہؒ سے حاصل کیا ہے تو اہلِ بصرہ احناف بنے۔
امام وکیع بن الجراحؒ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہؒ کی وفات کے بعد لوگ امام زفرؒ سے پڑھتے تھے اور بہت کم امام ابو یوسفؒ کی مجلس میں ہوتے تھے۔ امام زفرؒ ۱۵۸ھ میں فوت ہوئے تو آپ کے شاگرد بھی امام ابو یوسفؒ سے پڑھنے لگے (اخبار ابی حنیفہ للصمیری ص ۱۰۶)
(۳) امام محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانیؒ
(ولادت ۱۳۲ھ وفات ۱۸۹ھ) آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ جس دن امام ابوحنیفہؒ دنیا سے رحلت کر گئے امام محمدؒ اس دن اٹھارہ سالہ نوجوان تھے۔ آپ نے فقہ حنفی کی باقی تعلیم امام ابو یوسفؒ سے حاصل کی۔ اس کے بعد امام سفیانؒ ثوری اور امام اوزاعیؒ سے پڑھا۔ پھر تین سال مدینہ منورہ میں امام مالکؒ سے مزید احادیث کی تعلیم حاصل کی۔ اور جب وہ درس و تدریس کے لیے بیٹھ گئے تو بڑے ائمہ کرام نے آپ سے تعلیم حاصل کی جس میں امام محمد بن ادریس الشافعیؒ بھی ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں جب امام محمدؒ بات کرتے تو سننے والا یہ گمان کرتا کہ قرآن مجید امام محمدؒ کی لغت (لہجہ) میں نازل ہوا ہے۔
آپ نے فقہ حنفی امام اعظم ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ سے حاصل کی اور عراقی فقہ کے کامل مستند فقیہ بنے۔ اس کے بعد آپ نے حجازی فقہ امام مالکؒ شیخ الحجاز سے حاصل کی۔ اس کے بعد فقہ اہل الشام کی مہارت اہلِ شام کے امام اوزاعیؒ سے حاصل کی۔ آپ کی علمی خدمات کی بدولت آپ کے شاگردوں میں امام شافعیؒ جیسے لوگ پیدا ہوئے اور وہی امام شافعیؒ امام احمدؒ بن حنبل، امام داود الظاہریؒ، امام ابو جعفر طبریؒ اور امام ابو ثور بغدادیؒ کے استاد بنے۔ اس لحاظ سےمذہب شافعی اور مذہب حنبلی دونوں مذہب حنفی کی شاخیں ہیں۔ اور فقہی مسائل میں اختلاف نے اگر امام محمدؒ، امام زفرؒ اور امام ابویوسفؒ کو مذہب حنفی سے نہیں نکالا تو یہ اختلاف امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کو حنفیت سے کیسے نکالے گا؟ امام شافعیؒ فرماتے ہیں میں نے حلال و حرام، ناسخ و منسوخ میں امام ابوحنیفہؒ سے بڑا عالم نہیں دیکھا (اخبار ابی حنیفہ للصمیری ص ۱۲۳) اور فرمایا اگر لوگ فقہاء کے بارے میں انصاف کرتے تو وہ جان لیتے کہ انہوں نے محمد بن الحسنؒ جیسا فقیہ نہیں دیکھا (اخبار ابی حنیفہ للصمیری ص ۱۲۴)۔
یاد رہے کہ امام شافعی امام مالکؒ کے شاگرد بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ امام محمدؒ کو بے مثال امام سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معروف مصری محقق محمد ابوزہرہؒ نے اپنی کتاب اصول الفقہ مبحث المجتہدین میں لکھا ہے کہ قرنِ ثانی اور قرنِ ثالث کے کئی علماء کا یہ ہی نظریہ ہے کہ امام محمدؒ بن الحسن الشیبانی اپنے استاذ امام مالکؒ سے بڑے فقیہ تھے اور فنِ حدیث میں ان کے اوپر سبقت حاصل کی۔ امام احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دقیق مسائل امام محمد بن الحسن الشیبانیؒ کی کتابوں سے لیے (اخبار ابی حنیفہ للصمیری ص ۱۲۵)۔
امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کو عام کرنے میں اہم خدمت کی اور انہوں نے کئی کتابیں تالیف کیں۔ فقہ میں آپ کی تالیفات دو قسم کی ہیں:
(۱) ظاھرالروایۃ
جن کتابوں کو ثقہ اور معتمد علماء جو عوام میں مشہور و معروف تھے انہوں نے امام محمدؒ سے روایت کیا وہ کتب ظاہر الروایۃ یا اصول کے نام سے موسوم ہیں۔ وہ چھ کتابیں ہیں:
(۱) المبسوط (الاصل) ۔ (۲) الجامع الکبیر (۳) الجامع الصغیر (۴) کتاب السیر الکبیر (۵) کتاب السیر الصغیر (۶) الزیادات۔
یہ کتب ظاہر الروایۃ، احادیث آثار (اقوال صحابہؓ اور اقوال تابعینؒ) پر مشتمل ہیں۔ علماء امت نے مذہب حنفی کو باقی مذاہب اہل السنۃ والجماعۃ سے زیادہ صحیح پایا اور اسے اختیار کیا۔ انہوں نے ان کتابوں کے شروح لکھے اور بعض علماء نے انہیں مختصر کیا جنہیں متونِ اربعہ کہتے ہیں:
(۱) کنز الدقائق (۲) مختصر الوقایہ (۳) مختصر القدوری (۴) المختار، جس کے مصنف عبد اللہ بن محمود موصلی الحنفی ہیں۔
یہ چاروں کتب علماء اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک نہایت ہی مستند ہیں اور راقم الحروف کی رائے میں آخری کتاب ’’المختار‘‘ باقی تینوں کتب سے افضل اس لیے ہے کہ وہ مسائل میں امام ابوحنیفہؒ کے قول کو ذکر کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کتاب کی شرح ’’والاختیار لتعلیل المختار‘‘ کے نام سے لکھی اور ہر مسئلہ کے لیے قرآن و حدیث سے دلیلیں لکھیں جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام اعظمؒ کا کوئی قول بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی عیاں ہوئی کہ امام ابوحنیفہؒ رائے پر عمل نہیں کرتے بلکہ قرآن و حدیث سے حاصل شدہ علم کو امام ابوحنیفہؒ نے ’’رائے‘‘ سے تعبیر کیا۔ امام ابوحنیفہؒ نے کبھی کسی صحیح حدیث کو رد نہیں کیا بلکہ ضعیف حدیث کے لیے بھی قیاس چھوڑا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ نماز میں قہقہہ (زور سے ہنسنا) از روئے قیاس ناقض وضو نہیں کیونکہ انسانی جسم سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی امام ابوحنیفہؒ کو حدیث پہنچی، جو نماز میں زور سے ہنسا تو وہ نماز اور وضو لوٹائے، امام ابوحنیفہؒ نے قیاس چھوڑا اور فرمایا قہقہہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ امام شافعیؒ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے اور قیاس سے متصادم ہے۔
(۲) نادر الروایۃ
جن کتابوں کی روایت مشہور ثقہ علماء سے نہیں ہے وہ کتابیں نادر الروایۃ کہلاتی ہیں جن میں مشہور الامالی، الکیسانیات، الرقیات، اطعارونیات، الجرجانیات اور کتاب المخارج ہیں۔
امام محمد بن الحسنؒ انتہائی خوددار انسان تھے۔ ایک دن ہارون الرشید خلیفہ عباسی کے قصرِ خلافت میں تھے، خلیفہ باہر سے آئے، امام محمدؒ کے علاوہ تمام وزراء اور اہلِ دربار کھڑے ہوئے۔ کسی درباری نے ہارون الرشید سے تذکرہ کیا، آپ امام محمدؒ سے پوچھا۔ امام محمدؒ نے جواب دیا، آپ نے مجھے عالم مان کر قاضی مقرر کیا ہے، میں علم کی توہین نہیں کرتا اس لیے کھڑا نہیں ہوا، خلیفہ خاموش ہوا۔
(۵) امام الحسن بن زیاد الؤلؤی الکوفی
(المتوفی ۲۰۴ھ) امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں میں ایک بڑے محدث عالم ہیں، انہوں نے امام ابوحنیفہؒ سے مسند اور دوسری کتب، کتاب المجرد، کتاب ادب القاضی، کتاب الخصال، کتاب معانی الایمان، کتاب النفقات، کتاب الخراج، الفرائض، کتاب الوصایا کی روایت کی۔ انہوں نے محدث ابن جریحؒ سے بارہ ہزار احادیث کی روایت کی۔ امام یحیٰی بن آدمؒ فرماتے ہیں میں نے الحسن بن زیادؒ سے کوئی بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔
مذاہب اہل السنۃ والجماعۃ کی تاسیس ایک نظر میں
الاستاذ محمد امین درانی

انسانی حقوق کا اسلامی تصور
مولانا مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی
انسانی طرز عمل انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا ہونا چاہیئے؟ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں زندگی کی پوری اسکیم کا عملی نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔
- اس اسکیم کا ایک حصہ ہماری اخلاقی تعلیم و تربیت ہے جس کے مطابق افراد کی سیرت اور ان کے کردار کو ڈھالا جاتا ہے۔
- اس اسکیم کے مطابق ہمارا معاشرتی اور سماجی نظام تشکیل پاتا ہے جس میں مختلف قسم کے انسانی تعلقات کو منضبط کیا جاتا ہے۔
- اس اسکیم کا ایک حصہ ہمارے معاشی اور اقتصادی نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے جس کے مطابق ہم دولت کی پیدائش، تقسیم، تبادلے اور اس پر لوگوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں۔
- اور اس اسکیم کا ایک جز ہمارا سیاسی نظام ہے جس میں اس اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے سیاسی اقتدار کی ضرورت ہے۔
اس پوری اسکیم کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کے نظام کو معروفات پر قائم کرنا اور منکرات سے پاک کرنا ہے۔ یہ اسکیم سوسائٹی کے پورے نظام کو اس طرز پر ڈھالتی ہے کہ
- خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ایک ایک بھلائی اپنی پوری پوری صورت میں قائم ہو، ہر طرف سے اس کو پروان چڑھنے میں مدد ملے اور ہر وہ رکاوٹ جو کسی طرح اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے دور کی جائے۔
- اسی طرح فطرتِ انسانی کے خلاف ایک ایک برائی کو چن چن کر زندگی سے نکالا جائے، اس کی پیدائش اور نشوونما کے اسباب دور کیے جائیں، جدھر جدھر سے وہ زندگی میں داخل ہو سکتی ہے اس کا راستہ بند کیا جائے، اور اس سارے انتظام کے باوجود اگر وہ سر اٹھا ہی لے تو اسے سختی سے دبا دیا جائے۔
معروف و منکر کے متعلق یہ احکام ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اسکیم ایک صالح نظامِ زندگی کا پورا نقشہ دیتی ہے اور اس غرض کے لیے فرائض اور حقوق کا ایک پورا نظام ہے، ایک مکمل نقشہ ہے۔ ایک پوری اسکیم ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصہ کے ساتھ اعضائے جسمانی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اس اسکیم کا ایک حصہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ عرب کے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چارٹر اس وقت پیش کیا تھا جب نہ کسی اقوامِ متحدہ کا وجود تھا اور نہ انسان مادی ترقی کی اس معراج پر پہنچا تھا جہاں آج نظر آتا ہے۔
(۱) انفرادی حقوق
(۱) مذہبی آزادی
’’دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے‘‘۔ (البقرہ ۲۵۶)
’’اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟‘‘ (یونس ۹۹)
یعنی حجت اور دلیل سے ہدایت و ضلالت کا فرق کھول کر رکھ دینے کا جو حق تھا وہ تو پورا پورا ادا کر دیا گیا ہے۔ اب رہا جبری ایمان، تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزاد رکھنا چاہتا ہے۔
(۲) عزت کے تحفظ کا حق
’’اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں‘‘۔ (الحجرات ۱۱)
ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کی دل آزاری، ایک دوسرے سے بدگمانی درحقیقت ایسے اسباب ہیں جن سے آپس کی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسرے اسباب سے مل کر ان سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اسلام ہر فرد کی بنیادی عزت کا حامی ہے جس پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔
(۳) نجی زندگی کے تحفظ کا حق
’’اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو‘‘۔ (الحجرات ۱۲)
یعنی لوگوں کے دل نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا، اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی کھوج کرنا ایک بڑی بداخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی نجی زندگی کے تحفظ کا حق دیا گیا ہے اور دوسروں کو اس میں دخل اندازی سے روکا گیا ہے۔
(۴) صفائی پیش کرنے کا حق
’’تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں بخوبی جانتا ہوں‘‘۔ (الممتحنہ ۱)
یہ اشارہ بدری صحابی حضرت حاطبؓ بن بلتعہ کی طرف ہے۔ مشرکینِ مکہ کے نام ان کا ایک خط مکہ معظمہ پر حملہ کی خبر کے بارے میں پکڑا گیا تھا۔ مگر اس سنگین جرم کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلے عام اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا پورا موقعہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرم کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اسلام نے انسان کے اس بنیادی حق کی پاسبانی نازک سے نازک موقعہ پر بھی کر دکھائی ہے۔
(۵) اظہارِ رائے کی آزادی
قرآن مجید کی سورہ الشورٰی کی آیت ۳۸ میں فرمایا کہ وہ اپنے معاملات آپس کے مشورہ سے چلاتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۹ اس طرح ہے کہ:
’’(اے پیغمبرؐ!) ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریکِ مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم (مشورے کے نتیجہ میں) کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔‘‘
مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے۔ مشاورت کا اصول اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے اس کا متقاضی ہے کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفادات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو، اور مشورہ دینے والے اپنے علم، ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے دے سکیں۔
(۲) سماجی حقوق
(۱) انسانی مساوات
’’کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے‘‘۔ (الاحزاب ۳۶)
یہ مذکورہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زیدؓ کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؓ بنت جحش سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حضرت زینبؓ کو اپنے نسلی اور خاندانی فخر کے باوجود اس حکم کے سامنے سر جھکانا پڑا اور اس طرح نسلی امتیاز کے بت کو توڑ کر انسانی مساوات کا بہترین عملی نمونہ کاشانۂ نبوت سے سماج کے سامنے پیش کیا گیا۔
(۲) اجر و ثواب میں مرد و زن کی برابری
’’جو مرد اور عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے‘‘۔ (الاحزاب ۳۵)
یہ اسلام کی وہ بنیادی قدریں ہیں جنہیں ایک فقرے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان دائرۂ عمل کا فرق تو ضرور ہے مگر اجر و ثواب میں دونوں مساوی ہیں۔
(۳) والدین کے لیے حسنِ سلوک
’’ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے‘‘۔ (العنکبوت ۸)
انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ صاف ستھرے سماج کے قیام کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے۔
(۴) انسانی جان کی حرمت
’’اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے‘‘۔ (الفرقان ۶۸)
ایک دوسری جگہ بلا خطا کسی کی جان لینے کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ انسانی جان کی حرمت سماج کے ان بنیادی حقوق میں سے ہے جس کے بغیر کوئی سماج زندہ نہیں رہ سکتا۔
(۵) ازدواجی زندگی
’’اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی‘‘۔ (الروم ۲۱)
ایک پاکیزہ سماج میں یہ ضروری ہے کہ شادی کے قابل لوگ زیادہ دیر مجرد نہ رہیں تاکہ بلاوجہ کی شہوانی لہر سماج کی فضا کو زہرآلود نہ کر سکے۔ شادی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے لیے سکون و اطمینان کے ساتھ مؤدت و رحمت وہ بنیادی چیز ہے جو انسانی نسل کے برقرار رہنے کے علاوہ انسانی تہذیب و تمدن کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی بدولت گھر بنتا ہے، خاندان اور قبیلے وجود میں آتے ہیں، اور اس کی بدولت انسانی زندگی میں تمدن کا نشوونما ہوتا ہے۔ اس لیے ازدواجی زندگی ایک سماجی حق بھی ہے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت اور طریقہ قرار دے کر اس کو عبادت کا تقدس بھی بخش دیا ہے۔
(۳) سیاسی حقوق
(۱) اسلام کے سیاسی نظام کی اولین دفعہ
’’اے ایمان لانے والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ امر ہوں‘‘۔ (النساء ۵۹)
قرآنِ مجید کی یہ آیت اسلام کے سیاسی نظام کی بنیادی اور اولین دفعہ ہے۔ اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی واحد عملی صورت ہے۔ رسولؐ ہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ اولی الامر کی اطاعت خدا اور رسولؐ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔
(۲) عمومی اور مقصدی تعلیم
اسلام کے سیاسی نظام میں عمومی اور مقصدی تعلیم کا ایک بنیادی حق ہے۔ ارشاد ہے:
’’ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقہ کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں‘‘۔ (التوبہ ۱۲۱)
(۳) سیاسی ولایت کا حق
اسلام کے سیاسی نظام میں ولایت کا حق صرف ان باشندوں کو ہے جو اسلامی مملکت کی حدود میں ہوں۔ لیکن اخوت کا رشتہ بدستور ہے اور بین الاقوامی ذمہ داریوں نیز اخلاقی حدود کا پاس رکھتے ہوئے مظلوم کی امداد مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا:
’’وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے (دارالسلام میں) نہیں آئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن ایسی کسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے‘‘۔ (الانفال ۷۲)
(۴) سیاسی سربراہ منتخب کرنے کا حق
اسلام کے سیاسی نظام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ قوم کے معاملات چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے، اور وہ قومی معاملات کو ایسے صاحبِ رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابلِ اعتماد سمجھتی ہو، اور وہ اس وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربراہ بنائے رکھنا چاہے۔ یہ چیز ’’امرھم شورٰی بینھم‘‘ (الشورٰی ۳۸) کا ایک لازمی تقاضا اور سیاسی نظام کی ایک اہم دفعہ ہے۔
(۵) بے لاگ انصاف کا حصول
’’مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں‘‘۔ (الشورٰی ۱۵)
اسلام کے سیاسی نظام میں بے لاگ اور سب کے لیے یکساں انصاف مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے۔
(۶) حقوق کی یکسانیت
بہترین نظام وہ ہے جس میں ہر ایک کے حقوق یکساں ہوں۔ یہ نہیں کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے کسی کو مراعات و امتیازات سے نوازا جائے اور کسی کو محکوم بنا کر دبایا، پیسا اور لوٹا جائے۔ اسلامی نظامِ حکومت میں نسل، رنگ، زبان، یا طبقات کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ البتہ اصول اور مسلک کے اختلاف کی بنا پر سیاسی حقوق میں یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اصولوں کو تسلیم کرے وہی زمامِ حکومت سنبھال سکتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کی حکومت کی برائی ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:
’’واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا‘‘۔ (القصص ۴)
(۴) اقتصادی حقوق
(۱) قرآن کا معاشی نقطۂ نظر
’’تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی‘‘۔ (بنی اسرائیل ۳۰ و ۳۱)
قرآن مجید کا معاشی نقطۂ نظر، جو مذکورہ آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ رزق اور وسائلِ رزق میں تفاوت بجائے خود کوئی برائی نہیں ہے، جسے مٹانا اور مصنوعی طور پر ایک بے طبقات سوسائٹی پیدا کرنا کسی درجہ میں بھی مطلوب ہو۔ صحیح راہِ عمل یہ ہے کہ سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانینِ عمل کو اس انداز پر ڈھال دیا جائے کہ معاشی تفاوت کسی ظلم و بے انصافی کا موجب بننے کے بجائے ان بے شمار اخلاقی، روحانی اور تمدنی فوائد و برکات کا ذریعہ بن جائے جن کی خاطر ہی دراصل خالقِ کائنات نے اپنے بندوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت رکھا ہے۔
کھانے والوں کو گھٹانے کی منفی کوشش کے بجائے افزائشِ رزق کی تعمیری کوششوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ اے انسان! رزق سانی کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین میں بسایا ہے۔ جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا۔ تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی اتنے ہی معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے۔
(۲) دولت کی گردش
’’تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے‘‘۔ (الحشر ۷)
اس آیت میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتا رہے، یا امیر روز بروز امیر تر اور غریب دن بدن غریب تر ہوتے چلے جائیں۔ اس مقصد کے لیے سود حرام کیا گیا، زکوٰۃ فرض کی گئی، مالِ غنیمت میں خمس مقرر کیا گیا، صدقات کی تلقین کی گئی۔ مختلف قسم کے کفاروں کی ایسی صورتیں تجویز کی گئیں جن سے دولت کے بہاؤ کا رخ معاشرے کے غریب طبقات کی طرف پھر جائے۔ میراث کا ایسا قانون بنایا گیا کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے۔ اخلاقی حیثیت سے بخل کو سخت قابلِ مذمت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا۔ غرض وہ انتظامات کیے گئے کہ دولت کے ذرائع پر مالدار اور با اثر لوگوں کی اجارہ داری قائم نہ ہو اور دولت کا بہاؤ امیروں سے غریب کی طرف ہو جائے۔
(۳) ناپ تول میں کمی نہ ہو
’’وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو‘‘۔ (الاعراف ۸۵)
انسان کے معاشی حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ خریدار کو اس کے پیسے کے بدلے میں پوری اور بے میل چیز ملے۔ اسلام تجارت میں دیانت داری کو ایک پالیسی سے زیادہ ایک فرض کے طور پر ابھارتا ہے۔
(بشکریہ ماہنامہ دارالسلام، مالیر کوٹلہ)
’’وانہ لعلم للساعۃ‘‘ کی تفسیر اور پادری برکت اے خان
محمد عمار خان ناصر
سیالکوٹ کے ایک مسیحی عالم ماسٹر برکت اے خان اپنی کتاب ’’تبصرہ انجیل برناباس‘‘ میں لکھتے ہیں:
’’قرآن مجید میں جناب عیسٰی المسیح کی صلیبی موت کی منفی نہیں کیونکہ لکھا ہے کہ ’’اور تحقیق وہ (عیسٰی) البتہ علامت قیامت کی ہیں‘‘ (سورہ زخرف ۶۱) ترجمہ: شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ۔۔۔۔ قیامت کے معنی ہیں دوبارہ زندہ ہونا۔ چنانچہ جب عیسٰی المسیح مصلوب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ ان کی قیامت کی علامت اور نشان تھا۔ لہٰذا قیامت کے بارے میں شک کرنے والوں کو جناب عیسٰی المسیح کی زندہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ روزِ قیامت کے بارے میں شک نہ کرو۔ جس طرح عیسٰی المسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے اسی طرح روزِ قیامت تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔‘‘ (ص ۶۴)
(۱) پادری صاحب موصوف نے سورہ زخرف کی جو ۶۱ ویں آیت درج کی ہے اس کی تفسیر شیخ الاسلام علامہ عثمانیؒ کے قلم سے ملاحظہ کیجئے:
’’(مسیح کا) دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہو گا۔ ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ قیامت بالکل نزدیک آ گئی ہے‘‘۔ (فوائد)
معلوم ہوا کہ یہ آیت کلمۃ اللہ المسیحؑ کی آمد ثانی سے متعلق ہے، اناجیل اربعہ کی مزعومہ قصۂ قیامت مسیح سے اس آیت کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔
(۲) آیتِ مذکور میں اصل لفظ ’’الساعۃ‘‘ ہے جو اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے، قیامت کا لفظ ترجمہ میں استعمال ہوا ہے۔ ’’وانہ لعلم للساعۃ‘‘ عیسٰیؑ قیامت کی نشانی ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ اصل عربی لفظ کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں قیامت سے مراد ’’تیسرے دن جی اٹھنا‘‘ ہے۔ علاوہ ازیں کس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قصہ باطلہ قیامت مسیح مشار الیہ ہے؟
(۳) آیت کریمہ میں مسیحؑ (کی آمد ثانی) کو قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس پادری برکت صاحب لکھتے ہیں:
’’جب عیسٰی المسیح مصلوب تیسرے دن مردوں میں جی اٹھے تو یہ ان کی قیامت کی علامت اور نشان تھا۔‘‘
یعنی ’’قیامتِ مسیح‘‘ قیامت کا نشان ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو جبکہ قیامت مسیحؑ واقع ہو چکی ہے تو قرآن کریم میں حتمی الفاظ میں قیامت مسیح کو روزِ قیامت کی علامت قرار دینا کیسے جائز ٹھہرا کیونکہ آیت شریفہ میں پچھلے کسی قصہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ آئندہ ظہور پذیر ہونے والی آمد ثانی کا ذکر ہے۔ پادری صاحب کے مفروضہ کے بموجب آیت میں قیامت مسیح کا ذکر ہے تو لازم آتا ہے کہ قیامت مسیح تاحال ظہور پذیر نہ ہوئی ہو بلکہ قریب قیامت ظاہر ہونی ہو۔
(۴) ’’اور بے شک عیسٰیؑ قیامت کی علامت ہیں۔ سو تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو‘‘۔
پادری صاحب لکھتے ہیں:
’’روزِ قیامت کے بارے میں شک نہ کرو جس طرح عیسٰی المسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے اسی طرح روزِ قیامت تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔‘‘
۔۔۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ روز قیامت بارے شک کرنے والوں کو تنبیہ ہے لیکن اس کو مسیحؑ کے مردوں میں سے اٹھنے سے کیا ربط و علاقہ ہے؟ پادری صاحب آیتِ کریمہ سے قیامتِ مسیح اور صلیبی موت کا اثبات کرنے تو چل نکلے ہیں لیکن عربی زبان سے ناواقفی اور اصولِ تفسیر سے بے گانگی کے باعث اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے ۔۔۔
؏ اے بادِ صبا ایں ہمہ آوردہ تست
حفاظتِ قرآن کا عقیدہ اور پادری کے ایل ناصر
محمد عمار خان ناصر
حفاظتِ قرآن کا مسئلہ امتِ مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، کسی زمانے میں بھی کسی مسلمان عالم یا فاضل نے اس پر شک کی گنجائش نہیں دیکھی۔ البتہ روافض میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہا۔ اس مسئلہ کو اگرچہ اس گمراہ فرقہ کے بعض مشاہیر علماء نے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی تاہم ان کا قول قطعاً بے دلیل و بے حجت ہے۔ دورِ حاضر کے مشہور ایرانی دانشور اور مصنف جناب مرتضٰی مطہری قرآن میں تحریف کے قائلین کو ’’متعصب یہودی اور عیسائی‘‘ قرار دیتے ہیں (دیکھئے ان کی کتاب ’’وحی و نبوت ص ۶۹)۔
عیسائی پادریوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بائیبل محرف کو قرآن کے بالمقابل لایا جائے، یا پھر قرآن کریم کی عظمت و صداقت کے بارے میں شبہات ڈالے جائیں۔ چنانچہ اکثر لاٹ پادریوں نے خودساختہ مطالب اخذ کرتے ہوئے اور روایات کا تیاپانچہ کرتے ہوئے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ۔۔۔۔ پاکستان میں آج کل بالخصوص پادری صاحبان کے مجددین و محقققین اس مسئلہ پر خامہ فرسائی میں مصروف ہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب گوجرانوالہ تھیولاجیکل سیمنری کے چیف اور مسیحی ماہنامہ ’’کلام حق‘‘ کے مدیر اعلیٰ پادری کے ایل ناصر ہیں جو ماہرِ اسلامیات و عربی دان ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور اس کا ثبوت دینے کی کوشش میں ۔۔۔۔ اسلامی علوم کی مضحکہ خیز حد تک غلط تعبیر کے مرتکب بھی ہوئے۔ ۱۰ فروری ۱۹۹۰ء کو بذریعہ ڈاک ان کا ایک قلمی مقالہ موصول ہوا جو ۲۸ صفحات پر مشتمل ہے، اس میں نہ صرف پادری موصوف نے قرآن کریم کے متن کے ’’بچھا کچھا‘‘ ہونے کو قطعی نتیجہ قرار دیا بلکہ روایات سے یہ ثابت کرنے کی کوششِ نامراد کی کہ قرآن کریم کا متن محفوظ نہ رہا۔ جس کو پڑھ کر بے اختیار لبوں پر یہ شعر آگیا ؎
پھر آج آئی تھی اک مرجۂ ہوائے طرب
سنا گئی فسانے اِدھر اُدھر کے مجھے
آئیے پادری صاحب کی تحقیق کا مطالعہ بھی کریں۔
(۱) مختصرًا گزارش یہ ہے کہ قرآنِ کریم کا متن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا، تاہم یکجا جمع و مرتب نہ تھا۔ حضورؐ کی وفات کے بعد جنگ یمامہ تک کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ قرآن کریم جمع ہو جانا چاہیئے۔ حضرت عمرؓ نے جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکرؓ خلیفہ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو راضی کیا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خلیفہ ابوبکرؓ نے زید بن ثابتؓ کے ساتھ پچھتر اصحابؓ کی جماعت مقرر کی جنہوں نے قرآن کریم کی ہر آیت کو دو دو گواہوں یعنی حفظ اور کتابت کےبعد یکجا جمع کیا۔ نہایت احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کا مکمل متن ایک صحیفہ میں جمع کیا گیا۔ اس نسخہ میں منسوخ التلاوت آیات اور سبعۃ احرف بھی درج تھے۔
پھر حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب دیکھا گیا کہ مختلف قراءات کی وجہ سے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جائز قرار دیا تھا، ملک میں بَداَمنی پھیلنے کاخدشہ ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی قراءت کو درست کہتا تھا اور دوسرے کی قراءت کو غلط، تو حضرت عثمانؓ نے یہ کیا کہ مشاورت کے بعد قرآن شریف کی صرف ایک قراءت کو، جو کہ قریش کی تھی، مروّج کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کے پاس جو مختلف قراءت والے نسخے ہیں ان کو ختم کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر بَداَمنی ختم نہ ہو سکتی تھی۔ لہٰذا حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوبکرؓ والے مصحف سے قرآن کریم کو نقل کروایا اور حکم دیا کہ قریش کی قراءت نقل کی جائے۔ اس نسخہ میں منسوخ التلاوت آیات کو بھی نکال دیا گیا۔ اس نسخہ کی سات نقول مختلف مرکزی مقامات کو بھیج دی گئیں اور لوگوں سے باقی تمام نسخے لے کر جلا دیے گئے اور صرف ایک معتبر نسخہ رائج کر دیا۔
پادری صاحبان حضرت عثمانؓ کے اس کام کو تحریف قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے اپنی مرضی کی آیات رکھ کر باقی کو ضائع کر دیا جو کہ دلیل سے معرا ہے۔ پادری ناصر حضرت ابوبکرؓ کے جمع قرآن کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ:
’’قرآن شریف قاریوں کو زبانی یاد (حفظ) کرایا گیا تھا، بہت سے قاری قتل یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ نامعلوم قرآن شریف کا کتنا حصہ کس کس قاری کے ساتھ ہمیشہ تلف ہو گیا۔‘‘
ہم عرض کرتے ہیں کہ پادری صاحب نے کم فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ سمجھا ہے کہ ہر قاری کو الگ الگ قرآن یاد تھا، یا ہر قاری کو پورا قرآن یاد نہیں تھا، تاہم اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو خود بائبل کا متن بھی پادری صاحب کے بقول ہی محفوظ نہیں رہتا۔ پادری برکت اپنی کتاب ’’صحت کتب مقدسہ‘‘ میں کہتے ہیں کہ:
’’قیاصرہ روم کی ایذا رسانیوں اور حوادث زمانہ کے دستبرد سے یہ ہزاروں نسخے نہ بچ سکتے تھے اور نہ بچے۔‘‘ (ص ۲۲۰)
پادری صاحب کی بیان کردہ عبارت کی روشنی میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ بائیبل کا کافی حصہ ان نسخوں کی صورت میں ضائع ہو گیا تھا۔
؏ لو دام میں اپنے خود صیاد آگیا
(۲) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ:
’’جب قرآن شریف مصحف میں یکجا ہو گیا، برسوں آپ (یعنی حضرت عمرؓ) اس کی تصحیح میں سرگرم رہے اور بارہا صحابہؓ سے اس کے متعلق مناظرے کیے۔ کبھی حق اس لکھے ہونے کے موافق ظاہر ہوتا اور آپ اس کو اسی حالت میں رہنے دیتے اور لوگوں کو اس کی مخالفت سے منع کر دیتے۔ اور کبھی اس کے خلاف ظاہر ہوتا، اس حالت میں آپ اس آیت کو چھیل ڈالتے اور اس کی جگہ پر جو حق ثابت ہوتا لکھ دیتے۔‘‘ (ازالۃ الخفا ج ۲ ص ۲۱۱)
اس پر پادری صاحب کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے:
’’مندرجہ بالا بیان کا مفہوم بالکل صاف ہے کہ جس مصحف کو زید بن ثابتؓ نے حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ کے حکم سے جمع کیا تھا اس مجموعۂ متن پر حضرت عمرؓ کو مطلق اعتبار نہ تھا اور آپ نے کئی برس اس متن کی اصلاح و ترمیم کی اور اس کی تصحیح میں آپ سرگرم رہے اور صحابہؓ سے متن کی صحت اور عدمِ صحت کے بارے میں مناظرے کرتے رہے۔‘‘ ۔۔۔
حیرت ہے کہ حضرت عمرؓ کے پرخلوص کام اور محنت کو پادری صاحب الٹا انہیں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ کی رضا اور مشورہ ہی سے وہ مجموعہ متن تیار ہوا اور پادری صاحب اسے ان کے نزدیک ناقابل اعتبار ٹھہرا رہے ہیں ؎
ہم وفا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے
ایک نقطہ نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا
پادری صاحب نے فقط اپنی مرضی کا بیان چنا۔ ایسے واقعات اکا دکا اور بے ارادہ ہوئے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے کتاب کے اسی صفحہ پر ان کی مثال کے طور پر دو واقعات بھی بیان فرمائے ہیں:
- ایک قصہ کے مطابق حضرت عمرؓ کہیں جا رہے تھے کہ ایک آدمی کو آیت پڑھتے دیکھا، وہ صحیح پڑھ رہا تھا، حضرت عمرؓ کو محسوس ہوا کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے، احباب و اصحاب سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ صحیح وہی ہے جو وہ آدمی پڑھ رہا ہے۔ یہ مثال اس کی ہے جب کوئی آیت یا لفظ صحیح ثابت ہوا۔
- اور دوسرے قصہ کے مطابق ایک آدمی آیت میں قراءت شاذہ کو ملا کر پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اصحاب اور اس قراءت شاذہ کے استاد ابی بن کعبؓ وغیرہ سے معلوم کیا تو انہوں نے رجوع کر لیا اور حضرت عمرؓ کی بات مان لی۔
پادری صاحب کے دعوٰی کی حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے تعصب کی نگاہ سے شاہ صاحب کے بیان کو پڑھا اور لکھا ہے ؎
خواہش کا نام عشق نمائش کا نام حسن
اہلِ ہوس نے دونوں کی مٹی خراب کی
پادری صاحب نے مقالہ کا نام ’’قرآن شریف کے متن کا تاریخی مطالعہ‘‘ رکھا ہے، اس لیے مختلف نسخہ جات کا تعارف بھی ذکر کیا ہے۔ چونکہ ہم ’’حفاظتِ قرآن‘‘ کے برخلاف پادری صاحب کے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اس لیے ان تعارف و تبصرہ وغیرہ پر بالذات بحث نہیں کر سکتے۔ پادری صاحبان حضرت عثمانؓ کے دور میں جمع قرآن کو قرآن میں ردوبدل کا تاریخی واقعہ قرار دیتے ہیں لہٰذا قرآن پاک کو درحقیقت ’’تالیفِ عثمانی‘‘ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں پادری صاحب موصوف رقم طراز ہیں:
’’کتب احادیث و تفاسیر و تواریخ سے ظاہر ہے کہ حضرت عثمانؓ نے سوا زیدؓ بن ثابت نوجوان کے کسی اور کو قرآن شریف کے متن کو جمع کرنے کے لیے شامل نہ کیا۔ حضرت عثمانؓ نے قرآن شریف کی تنزیل کو بدل ڈالا۔ آپ نے قرآن شریف کی سات قراءتوں کو مٹا ڈالا اور ایک قراءت قریش مقرر کر دی۔ باقی کل مصاحف اور اوراق وغیرہ جو حضرت محمد صلعم کے زمانے میں لکھے گئے تھے اور حضرات شیخین کے زمانے تک محفوظ چلے آتے تھے اور تبرکات وحی تھے خود حضرت محمد صلعم نے اپنے کاتبوں سے لکھوایا تھا وہ قابلِ قدر اور قابلِ حفاظت تھے ان سب کو جلا دیا۔ حضرت عثمانؓ نے اس مہم میں تعاون نہ کرنے والوں پر بے حد سختی کی مثلاً عبد اللہ ابن مسعودؓ کے ساتھ، مروان بن حاکم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا محنت شاکہ سے جمع کیا ہوا قرآن اور عرق ریزی سے تصحیح کیا ہوا قرآنی متن بھی جلا ڈالا۔‘‘
ہم بالترتیب پادری صاحب کے دعاوٰی کا مطالعہ کریں گے:
(۱) یہ کہنا کہ حضرت عثمانؓ نے زیدؓ بن ثابت کے سوا کسی کو جمع قرآن میں شامل نہ کیا تھا، سراسر غلط ہے حافظ سیوطیؒ امام بخاری کے حوالہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:
فامر زید بن ثابت و عبد اللہ بن الزبیر و سعید ابن العاص و عبد الرحمان بن الحارث بن ھشام فنخوھا فی المصاحف (الاتقان ج ص ۵۹)
ترجمہ: ’’حضرت عثمان نے زید بن ثابت، عبد اللہ ابن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام کو نسخہ کو نقل کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مصاحف میں نقل کیا۔‘‘
(۲) حضرت عثمانؓ پر قرآن شریف کی تنزیل کو بدل ڈالنے کا جو الزام پادری صاحب نے لگایا ہے وہ حقیقت سے سراسر متضاد ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب نزولِ قرآن کے مطابق نہیں، لیکن یہ کسی انسان کا کارنامہ بھی نہیں کیونکہ جیسے جیسے وحی آتی جاتی تھی جبرئیل امین خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایات بھی دیتے تھے کہ اس آیت کو کون سی سورۃ میں کون سے نمبر پر رکھنا ہے۔ قرآن کریم کو اسی طرح حفظ کیا گیا اور اسی طرح نقل کیا گیا۔ پادری صاحب کی ہوشمندی دیکھیں کہ سات قراءتوں کے مٹ جانے پر بھی اصرار فرما رہے ہیں اور قراءت قریش کو بھی مان رہے ہیں ؎
بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی
بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں
بہرحال یہ الزام بھی مفروضہ اور ناقابلِ اعتماد، سماع و افواہ پر مبنی ہے۔ علامہ ابن حزمؒ رقم طراز ہیں:
واما قول من قال ابطل الاحرف الستۃ فقد کذب من قال ذلک ولو فعل عثمان ذلک او ارادہ لخرج عن الاسلام ولما مطل ساعۃ بل الاحرف السبعۃ کلھا موجودۃ عندنا قائمۃ کما کانت مثبوثۃ فی القرآت المشہورۃ الماثورۃ (الملل والنحل ج ۲ ص ۷۸)
ترجمہ: ’’یہ کہنا کہ عثمانؓ نے چھ حرف (قراءتیں) مٹا دیے تو جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر عثمانؓ ایسا کرتے یا ایسا کرنے کا ارادہ کرتے تو اسلام سے خارج ہو جاتے اور ایک ساعت بھی نہ ٹھہرتے۔ یہ ساتوں حروف (قراءات) ہمارے پاس موجود ہیں اور جیسے تھے ویسے ہی قائم ہیں، مشہور و منقول و ماثور قراءتوں میں محفوظ و ثابت ہیں۔‘‘
پادری صاحب کو اسلامی علوم کی ہوا بھی لگی ہوتی تو اس قدر غلط بیانی نہ کرتے۔ بزعم خویش محقق بننے سے کچھ نہیں ہو جاتا اس کے لیے کچھ قابلیت چاہیئے۔
(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خود لکھوائے ہوئے تبرکاتِ وحی اور قابلِ قدر و قابلِ حفاظت مصاحف و اوراق کے جلانے کا تذکرہ بالخصوص کہیں نہیں ملتا، اور اگر جلا بھی دیا تھا تو وہ سارے تبرکات حضرت ابوبکرؓ نے نقل فرما لیے تھے، اس میں کون سی قیامت آگئی؟ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا ’’محنتِ شاکہ‘‘ سے جمع کیا ہوا قرآن بجنسہ ہمارے پاس موجود ہے۔ علماء نے جمع صدیقی اور جمع عثمانی میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ جمع عثمانی میں منسوخ آیات اور سبعۃ احرف نہیں تھے کیونکہ سبعہ احرف کی اجازت ابتدائی دور اور حالات کے پیشِ نظر تھی اور بعد میں ان کی وجہ سے امت میں افتراق پیدا ہونے کا خدشہ تھا بلکہ تقریباً ہو چکا تھا۔
(۴) حضرت عبد اللہ ؓ ابن مسعود کے ساتھ سختی اس لیے کی کہ وہ صحابہ کرامؓ کے اتفاق کے برخلاف کام کر رہے تھے۔ اس وقت امت میں افتراق ایک بہت بڑا حادثہ ثابت ہوتا اور پھر حضرت عبد اللہ ؓ ابن مسعود نے اپنے موقف پر اصرار بھی نہیں کیا بلکہ رجوع فرما لیا تھا اور جمع قرآن کی مخالفت نہ کی تھی۔ حافظ ابن کثیر کی تاریخ میں لکھا ہے:
فاناب واجاب الی المتابعۃ و ترک المخالفۃ (البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۲۱۸)
ترجمہ: ’’عبد اللہ ابن مسعودؓ نے رجوع کر لیا اور پیروی کرنے اور مخالفت ترک کرنے کا وعدہ کیا۔‘‘
ابن سعد کہتے ہیں کہ دونوں بزرگوں میں صلح صفائی ہو گئی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے استغفار کیا تھا۔ (دیکھئے طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۱۳)
اب ہم پادری صاحب کی پیش کردہ اس روایت پر بحث کریں گے جس کو انہوں نے نہ صرف موقع محل سے ہٹا کر بلکہ اس کی مسلم تفسیر سے علیحدہ من مانی تفسیر کر کے پیش کیا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب ’’الاتقان فی علوم القرآن‘‘ میں نسخ کی تیسری قسم ’’منسوخ التلاوت‘‘ کے تحت یہ روایت نقل فرمائی ہے:
عن ابن عمر قال لیقولن احدکم قد اخذت القراٰن کلہ و ما یدریہ ما کلہ قد ذھب منہ قراٰن کثیر ولکن لیقل قد اخذت منہ ما ظہر (ص ۲۵ ج ۲)
ترجمہ: ’’عبد اللہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ کہے گا کہ میں نے سارا قرآن لے لیا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ سارا قرآن کیا ہے۔ اس میں سے بہت سا حصہ چلا گیا ہے لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے اس سے وہی چیز لی ہے جو کہ ظاہر ہوئی۔‘‘
اس پر پادری صاحب کے الفاظ ملاحظہ ہوں:
’’بعض لوگ حضرت ابن عمرؓ کے اس قول ’’قد ذھب منہ قراٰن کثیر‘‘ کی تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آیات ہیں جو منسوخ التلاوت تھیں لیکن یہ تاویل بالکل غلط ہے کیونکہ اگر یہی تاویل مراد ہوتی تو ’’ذھب‘‘ کے عوض ’’نسخ‘‘ فرماتے اور پھر اس کو قرآن کثیر نہ فرماتے اور نہ اس پر افسوس کرتے کیونکہ منسوخ التلاوت آیات تو اس قابل نہیں کہ نکال دی جائیں۔ کیا کوئی شخص ایسا ہو گا کہ وہ اپنے ان اشعار یا عبارات پر افسوس کرتا ہو جن کو خود اس نے کاٹ دیا ہو یا نکال دیا ہو۔‘‘
اس مقام پر بھی ہم اس عبارت کا شق وار مطالعہ کریں گے:
(۱) یہ کہنا کہ ’’قرآن کثیر‘‘ سے مراد ’’منسوخ التلاوت‘‘ آیات ہیں، بعض کا نہیں بلکہ خود مصنف علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سیوطی اس روایت کو کس ضمن میں سمجھے ہیں:
الضرب الثالث ما نسخ تلاوتہ دون حکمہ ۔۔۔۔ وامثلۃ ھذا الضرب کثیرۃ قال ابوعبیدۃ حدثنا اسمٰعیل بن ابراھیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال ۔۔۔۔ (الاتقان ج ۲ ص ۲۴ و ۲۵)
ترجمہ: ’’(نسخ کی) تیسری قسم یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو گئی ہو اور حکم باقی ہو، اور اس قسم کے نسخ کی مثالیں بہت ہیں (دلیل یہ ہے کہ ) ابوعبیدۃ نے کہا کہ ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے، اس نے نافع سے، اس نے ابن عمرؓ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا ۔۔۔‘‘
جب صاحبِ کتاب نے خود اپنی مراد واضح کر دی تو پادری کس برتے پر چیلنج کرتے پھر رہے ہیں ؎
وہ کہ خالی ہاتھ پھیلائے فضا میں رہ گئے
منتشر کچھ اس طرح ہستی کا شیرازہ ہوا
(۲) ’’ذھب‘‘ اس لیے فرمایا کہ منسوخ التلاوت آیات کا حکم باقی ہے فقط قراءت ممنوع ہے۔ اور منسوخ الحکم والتلاوت اور منسوخ الحکم دونوں قسموں میں حکم جو کہ مقصود ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اس قسم ثالث میں حکم باقی ہے۔ لہٰذا ’’نسخ‘‘ کی بجائے ’’ذھب‘‘ فرمایا کیونکہ اصل مقصود چیز منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے ساری روایت کی حقیقت جس کو پادری صاحب نے ہوا بنا کر پیش کر دیا۔ قرآن کثیر فرما دیا تو کیا حرج ہوا؟ کوئی وجہ بھی تو بیان فرمائیں۔ باقی یہ کہنا کہ منسوخ التلاوت آیات اس قابل نہیں کہ نکال دی جائیں، یہ پادری صاحب کی نام نہاد علمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس کو خود منسوخ التلاوۃ کہہ رہے ہیں اس کو باقی رکھنے پر اصرار کا آخر معنٰی کیا ہے؟ نیز پادری صاحب کی حاشیہ آرائی دیکھئے کہ خواہ مخواہ افسوس اور غم ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سر تھوپ رہے ہیں۔ نامعلوم کس جملہ یا کس لفظ سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ پادری صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی علمیت کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائیں۔
قارئین! پادری صاحب کے ’’حفاظتِ قرآن‘‘ پر اعتراضات کو ملاحظہ کرنے اور ان کی صحت و سقم کو پرکھنے کے بعد ہم اس قطعی نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ قرآن شریف بحمدہ تعالیٰ اصل حالت میں نزول کے وقت سے لے کر ہم تک پہنچا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پادری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمانؓ نے اپنی مرضی کی آیات بھی اس میں ڈال دی تھیں۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کے بعد کسی دور میں بھی اس کا کوئی ثبوت پادری صاحبان پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ پھر یہ حقیقت کہ پادری صاحبان قرآن میں ادخال کا الزام نہیں لگاتے، اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن کریم سابقہ کتب کے برخلاف تحریف سے قطعی محفوظ و مصئون ہے کیونکہ اگر قرآن شریف میں تحریف ممکن الوقوع ہوتی تو یہ صرف حضرت عثمانؓ کے دور کے ساتھ مخصوص اور صرف اخراج و ضیاع تک محدود نہ ہوتی۔ فلہٰذا اس امر کی حیثیت محض مفروضہ اور وہم و گمان سے زیادہ نہیں ہے۔۔۔۔
دو قومی نظریہ نئی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے
مولانا سعید احمد عنایت اللہ
ایک ہی آدم حوا کی اولاد، ایک علاقہ کے باسی، ایک ہی بولی بولنے والے، ایک ہی رنگ و نسل بلکہ ایک ہی شکمِ مادر سے پیدا ہونے والے دو افراط کو نظریہ اور عقیدہ دو قومیں بنا دیتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:
’’اللہ تعالیٰ کی بزرگ و برتر ذات نے تم کو پیدا کیا، تم میں کوئی مومن ہے کوئی کافر‘‘ (التغابن)
اسلامی اور غیر اسلامی عقیدہ کے حامل دو اشخاص کا دو قومیت میں تقسیم ہونا خدائی عمل ہے۔ ظاہر ہےکہ ایمان و توحید کے حامل کا قلب و کردار و اعمال و طبیعت و افتاد الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں ایک مومن غیر مومن سے مختلف ہے۔ اس لیے کہ مومن کے لیے محور تو ذات حق تعالٰی ہے جن سے وہ زندگی کے ہر موڑ پر رشد و ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے حاصل کر کے قدم اٹھاتا ہے۔ وہ ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو کر مکمل طور پر ذاتِ برحق کی غلامی میں آجاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہے کہ اپنے ماحول و سوسائٹی کو بھی اسی نظریہ کی دعوت پر پورے وثوق کے ساتھ دے کہ انفرادی اور اجتماعی حیات اسی میں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:
’’اے ایمان والو! تم خدا اور رسولؐ کی مکمل اطاعت کو لازم پکڑو کہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔‘‘
یہی وہ عظیم فکر تھی اور عالی نظریہ تھا جس نے برصغیر کے بسنے والوں، چاہے وہ سب علاقائی اور لسانی طور پر متحد تھے، دو قومیں بنا دیا اور ان کا جغرافیائی اتحاد نظریاتی اختلاف کے سامنے تارِ عنکبوت بن گیا۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ، شاہ اسماعیل شہیدؒ، پھر تحریکِ خلافت کے روح رواں اور ہمارے مسلم زُعماء اسی نظریہ کے علمبردار تھے۔ برصغیر کے عوام کی مسلم اکثریت نے بھی اظہار کیا کہ مسلم اور ہندو ایک ساتھ ایک پرچم تلے زندگی نہیں گزار سکتے جبکہ ان کا عقیدہ، ایمان، تہذیب و تمدن الگ الگ ہے۔
مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پرچم تلے قائد اعظم، لیاقت علی خان، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا ظفر علی خان اور اپنے دیگر زعماء (رحمہم اللہ) کی قیادت میں ایک ایسے خطۂ ارض کا مطالبہ کیا جہاں وہ اسلامی نظریات اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وہ اسلامی ثقافت کے مطابق نشوونما پائیں اور اسلام کے عدلِ عمرانی کے اصول پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں۔ اسی لیے تو پورے برصغیر میں ہر بوڑھے بچے، لکھے پڑھے، ان پڑھ کی وردِ زبان تھا:
’’پاکستان کا مطلب کیا، لا الٰہ الا اللہ‘‘
متحدہ ہندوستان کے وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی اقلیت میں تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ پاکستان کے نقشے سے بعید ہیں وہ بھی اس مطالبے کے منوانے اور اس نظریاتی مملکت کے قیام کے لیے جہاد میں پیچھے نہ تھے۔ بلکہ ان کو تو قیامِ پاکستان کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، ان میں سے کچھ کو اپنے موطن و مولد کو چھوڑ کر ہجرت کا عظیم عمل کرنا پڑا اور خونی دریا عبور کر کے پاکستان پہنچے، کچھ وہیں مقیم رہے اور ہندو سامراج کے ظلم کا آج تک نشانہ بن رہے ہیں۔
مسلم قوم کی مالی و جانی اور بیش بہا قربانیوں کے صدقے وجود میں آنے والی ارضِ پاک کی حدود میں شریعتِ اسلامیہ کا نفاذ اس کا بنیادی حق اور باعثِ قیام ہے جس سے سرِمو انحراف ان تمام قربانیوں کو ضایع کرنے کے ساتھ ساتھ ان اکابر سے دھوکا اور اس رب العالمین سے غداری ہے جس کے نام کا کلمہ پڑھ کر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کس قدر ڈھٹائی ہے ان بے باک اور بدطینت افراد کی، چاہے وہ کسی بھی طبقہ یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، جو آج قیامِ پاکستان کے مقصد کی کچھ اور تفسیر کر کے نظریاتی تحریف کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قائد اعظم نے اکتوبر ۱۹۴۷ء میں مملکت کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے خطاب میں انہوں نے یہ فرمایا:
’’پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم گذشتہ دس سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے اب خدا کے فضل سے ایک حقیقتِ ثانیہ بن کر سامنے آ چکا ہے، لیکن ہمارے لیے اس آزاد مملکت کا قیام ہی مقصود نہیں تھا بلکہ یہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور جس میں ہم اپنی اسلامی روشنی اور ثقافت کے مطابق نشوونما پا سکیں اور اسلام کے عدلِ عمرانی کے اصول پر آزادانہ عمل کر سکیں۔‘‘
دو قومی نظریے کے عظیم قرآنی تصور نے مختلف لسانی اور علاقائی انسانی مجموعوں کو ایک اور صرف ایک قوم بنا دیا، پھر ۱۹۴۷ء میں دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اسلامی سلطنت کو وجود بخشا جس سے پورے عالم کے مسلمانوں کی بہت توقعات وابستہ تھیں اور ان کو دلی خوشی تھی کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی یہ نئی ریاست اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور ان کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کا سبب بنے گی، مگر بدقسمتی سے برسراقتدار طبقہ کی اکثریت نظریہ پاکستان سے قلبی و ذہنی طور پر لاتعلق تھی پھر نظریہ دشمن عناصر کی ریشہ دوانیاں۔ اسی طرح عظیم مقصد سے انحراف نے حالات کو ۔۔۔ کہ ۱۹۷۱ء میں ملک دولخت ہو گیا اور اس عظیم حادثہ کے بعد بھی پاکستان کے اہلِ اقتدار نے نظریہ پاکستان کی عملی طور پر پاسداری کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کی حفاظت میں تمام تر قوتوں کو صرف کر دیا تو علاقائی اور لسانی بنیادوں پر نئے فتنوں نے جنم لیا، مزید قومیتوں میں تقسیم ہونے کا احساس پیدا ہو گیا۔
کاش کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ اے کاش کہ ہم جان لیں، اہل اقتدار بھی اور عوام من حیث القوم کہ ہمارے معاشرے کی تمام خرابیوں کی جڑ اور ہمارے تمام حقوق کے استحصال کا موجب نظریۂ پاکستان سے عملاً انحراف ہے۔ اگر ہم وطن عزیز کو اس کا بنیادی حق دلا دیں اور اسلامی نظام کی تنفیذ سے کم کسی مطالبے کو تسلیم ہی نہ کریں تو ہماری تمام شکایتیں بھی دور ہو جائیں اور انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل بھی بطریق احسن ہو۔ اپنے اسلاف کی ارواح کو سکون بخشیں، ہماری طرف سے ان کی خدمت میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کی بہترین صورت یہی ہے۔ خدائے ذوالجلال سے کیے گئے وعدے کا ایفا بھی ہو جائے گا۔ قربانی دینے والوں کی قربانیوں کی بھی قدر ہو گی۔ آئندہ نسلوں کی بھی بہترین خدمت، جن کی اسلامی اصولوں پر نشوونما اور ذہنی فکری تربیت بھی مادی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمہ ہے۔ ان کی اصلاح سے ہم آرام سے رہیں گے اور عند اللہ ماجور ہی نہیں بلکہ ان کے عملی اور ذہنی بگاڑ پر ہم سے باز پرس ہو گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
’’والد کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ اس کی اعلیٰ تربیت ہے۔‘‘
اولاد اور نئی نسلوں کو ان کے اس حق سے محروم رکھ کر نہ ہم اس دنیا میں پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں نہ آخرت میں ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن حکیم میں ہے، بگڑی ہوئی نسلیں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے لیے اپنے سے دگنے عذاب کا مطالبہ پیش کریں گے کہ ان کی غلط روش نے اور ہماری تربیت میں کوتاہی نے ہمیں راہ راست سے دور رکھا اور ہم اپنی منزل نہ پا سکے۔ لہٰذا اس وقت نظریۂ پاکستان کی اہمیت کو بزرگ اپنی نئی نسلوں کے سامنے واضح کریں۔ نوجوانوں کو سمجھائیں، ہر ذی شعور اس کے لیے محنت اور کوشش کرے اور تعلیم و تربیت اور ابلاغ و اعلام کے جملہ وسائل کو اہلِ اقتدار اس عظیم مقصد کو سمجھانے کے لیے صرف کریں اور ہم پاکستانی بطور قوم نظریۂ پاکستان، اسلام کی عملی تنفیذ کے بغیر اپنے آپ کو سب سے بڑے حق سے محروم سمجھیں تاکہ نظریہ دشمن عنصر ہمارے ملک یا ہماری قوم کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث نہ بن سکیں اور ہم اپنے احوال کو بھی سنوار سکیں۔
بھارت میں اردو کا حال و مستقبل
بیگم سلطانہ حیات
آپ کو یاد ہو گا کہ تقسیمِ ہند کے بعد اردو کا چلن سکولوں وغیرہ میں سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا تھا اور پھر دستورِ ہند کی دفعہ ۳۴۳ کے تحت یہ طے پایا تھا کہ حکومتِ ہند کی سرکاری زبان ہندی ہو گی جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائے گی، اور پھر ۱۹۵۱ء میں دفعہ ۳۴۵ کے تحت ہندی کو یو پی کی سرکاری زبان بنا دیا گیا اور اردو کے وجود کو نظرانداز کر دیا گیا۔ ہم اردو والوں نے پنڈت کشن پرشاد کول صاحب کی زیرقیادت دستخطی مہم کا آغاز کیا اور لسانی تعصب کی تلواروں کی چھاؤں میں دستخطی مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اردو کا کاروان چلتا رہا، اور جس ریاست میں اردو کا وجود سرکاری طور پر ختم ہو گیا تھا اس کو درجہ آٹھ تک ذریعۂ تعلیم بنانے کی اجازت مل گئی، اور اب ہماری مانگ ہے کہ دسویں درجہ تک اردو کو ذریعہ تعلیم تسلیم کر لیا جائے، اردو کورس کی کتابوں کو شائع کرنے کا ایسا بندوبست کیا جائے کہ وہ سیشن شروع ہونے سے پہلے پورے صوبے میں بآسانی دستیاب ہو سکیں وغیرہ۔
مگر ان مراعات کو عملی جامہ پہنانے میں جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کام کرنے والے ہی جانتے ہیں، یہ صرف ہمارے ساتھ حکومت ہی کا برتاؤ نہیں ہے، سرکاری دفتروں میں درخواست کے ساتھ ساتھ جانا پڑتا ہے تب جا کر کام ہوتا ہے۔ اردو والوں کے حالات کچھ زیادہ سخت ہیں مگر محنت اور لگن سے کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب اردو دوستوں سے اپیل ہے کہ حکومت نے اردو کو جو مراعات دی ہیں ان کو اپنے حلقوں میں بروئے کار لانے کی ذمہ داری اب اردو والوں کی ہے۔ اردو سے محبت کے معنی ہیں کہ اس کی عملی خدمت کی جائے۔
حکومت اردو کو دوسری سرکاری زبان تسلیم کرنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے ایک حد تک سبک دوش ہو جائے گی اور اردو کا چلن دوبارہ شروع صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اترپردیش کے ہر گوشہ میں ان مراعات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔
اس کے علاوہ ہماری مانگ یہ بھی ہے کہ ہر تحصیل میں کم از کم دو اردو میڈیم سکول سرکار اپنے خرچ سے چلائے۔ مگر اس میں قباحت یہ ہے کہ پھر وہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، مثلاً بی ٹی سی (بیسک ٹیچرز سرٹیفیکیٹ) سینٹروں کو لیجئے، یہ بیسک ٹریننگ کالج (اردو) انجمن کی درخواست پر ٹیچروں کو اردو تعلیم دینے کے لیے وجود میں آئے تھے اور اب یہاں سب مضامین پڑھاتے ہیں سوائے اردو کے۔ ان کالجوں کی لائبریری کے لیے حکومت اب تک دو تین لاکھ روپے تو دے ہی چکی ہو گی مگر ایک پیسے کی بھی اردو کتابیں نہیں خریدی گئی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کالج جن کی تعداد ۴ ہے، مجھے اپنے متعلقہ لائبریری میں کسی ایک سال کی مالی امداد سے اردو کی کتابوں کے خریدنے کی رسید اور کتابیں دکھا دے تو میں اپنا بیان واپس لے لوں گی اور معافی مانگ لوں گی۔
ان حالات کے پیشِ نظر ہمارا مطالبہ ہے کہ بی ٹی سی پاس شدہ ٹیچروں کو عام ٹیچر تصور کیا جائے اور اس میں محکمۂ تعلیم کو کوئی قباحت بھی نہیں ہو گی، صرف سائن بورڈ ہی تو بدلنا ہو گا۔ اس تمام جدوجہد سے بچنے کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر تحصیل میں کسی اچھے دو اردو مکتبوں یا پرائیویٹ اردو اسکولوں کو حکومت اپنا لے۔ ٹیچروں وغیرہ کی تنخواہ دے تاکہ حکومت کے تعاون سے یہ مکتب یا سکول اپنا معیارِ تعلیم بلند کر سکیں اور پھر جلد ہی ان کو اردو میڈیم ہائی سکول میں تبدیل کر دیا جائے۔
اس جگہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ صوبہ میں اس وقت ۸۱۴ گرانٹ یافتہ مکاتب ہیں اور ہم ان مکاتب کی کھوج کر رہے ہیں جن کو پہلے گرانٹ ملی تھی اور اب بند ہو گئی ہے تاکہ ان کی گرانٹ پھر سے جاری کرائی جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے حکومت سے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان امداد یافتہ مکاتب کا انتظام موجودہ ناظم صاحبان کے ہاتھ میں پہلے کی طرح رہے اور اگر حکومت کا دخل ذرا بھی ہوا تو اردو تعلیم کا مقصد فوت ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ سرکاری جی او نمبر x17-110-59 / 10453 مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۵۹ء کی رو سے اردو میں رجسٹریاں بیعنامہ بغیر ہندی ترجمہ لگائے جا سکتے ہیں اور اس پر عمل سب سے پہلے قاضی عدیل عباسی مرحوم ایڈووکیٹ نے بستی میں کیا اور جب تک وہ زندہ رہے اس پر عمل ہوتا رہا۔ میں قاضی صاحب کی مثال ادھر بار بار دے رہی ہوں تاکہ ہمارے وکیل صاحبان اس طرف توجہ فرمائیں اور عدالتوں و کچہریوں میں اردو کا چلن پھر سے عام ہو جائے۔ میں جانتی ہوں کہ اب یہ کام آسان نہیں ہے لیکن ہمیں اگر اپنی مادری زبان سے محبت ہے تو یہ کرنا ہو گا۔
ایک بڑی کامیابی انجمن کو یہ ہوئی، جس کو بروئے کار لانے کے لیے یو پی کے ہر کونے میں محبانِ اردو کو سرگرم عمل ہونا چاہیئے، وہ یہ کہ حکومتِ ہند پورے ملک میں جہالت کے خلاف ایک تعلیمِ بالغاں مہم چلاتی ہے، تامل، تلگو، بنگالی وغیرہ، غرضیکہ شیڈول ۸ میں شامل ہر زبان کے لوگ اس مہم میں شرکت کر رہے ہیں سوائے اردو کے، انجمن کی کوششوں سے اردو ڈائریکٹوریٹ سے ایک خط نمبر کیمپ/بسیک/زبان 3-2683-2780 مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۸۹ء کو ہر بسیک شکشا ادھیکاری کے نام جاری ہو گیا ہے کہ وہ ۱۵ دن کے اندر اندر ڈائریکٹر اردو کو بتائیں کہ ان کے حلقے میں کس قدر اردو تعلیمِ بالغاں کی کلاسیں کھولی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے بسیک شکشا ادھیکاری صاحبان اس طرف کچھ خاص توجہ نہ دے پائیں گے اس لیے یہ کام اب محبانِ اردو کا ہے کہ وہ بالغوں اور ان کے بچوں کے لیے اردو کلاسیں کھلوانے کے لیے بسیک شکشا ادھیکاری صاحبان کو خود ہی لکھ دیں کہ ان کے حلقے میں کن کن محلوں میں اندازًا کتنی کلاسیں ان پڑھ مردوں، عورتوں اور بچوں کی کھل سکتی ہیں۔ اس کے بعد چپ نہیں بیٹھنا ہے انہیں یاددہانی کرانا ہے۔ جی ایس اے اور ضلع کے تعلیم بالغان افسر سے بھی ملنا ہو گا (کہ) اس تجویز پر عمل کیا؟ مثلاً مجھے آج ہی اطلاع ملی ہے کہ لکھنؤ شاخ کے ایک سرگرم کارکن جناب جمال علوی نے اس تجویز پر عمل کیا اور بدقت تمام ان ضلع کے تعلیم بالغان افسر سے تعلیم بالغان کتابوں کے Kits دیئے مگر اس میں اردو کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ اب اس کی شکایت بھی جناب نرائن دت تیواری جی سے کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ جلد ہی اردو کا سیٹ Kits بھی تیار ہو کر اردو والوں کی خدمت کے لیے آجائیں گے، مگر ہر طرف سے اردو کٹ کی مانگ کی ضرورت ہے۔
یہ سب کام پورے صوبے میں عملی جامہ پہن سکتا ہے بشرطیکہ آپ حضرات خود دلچسپی لیں۔ اب وہ زمانہ گیا جب کچھ مقامات پر انجمن کے کارکنوں نے ایک ایک سکول میں اردو جاری کرانے کے لیے پچیس تیس سال تک محنت کی ہے۔ اب تو ہر مقام کے اردو نواز حضرات کو سرگرمِ عمل ہونا چاہیئے۔ قالین پر بیٹھ کر غمِ اردو کو بیان کرنا بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے مگر اب وقت ہے عملی اقدام کا تاکہ حکومت کے نافذ کردہ قوانین کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔
مزید معلومات ’’ریاستی انجمن ترقی اردو‘‘ اترپردیش جی ۳/۴ رپورنک کالونی لکھنؤ سے حاصل کیجئے۔
(بشکریہ دیوبند ٹائمز)
جہادِ آزادیٔ کشمیر اور پاکستانی قوم کی ذمہ داری
مظفر آباد سے کشمیر کی ایک غیور بیٹی کا مکتوب
ادارہ
(کشمیری حریت پسند اس وقت فیصلہ کن جہادِ آزادی میں مصروف ہیں اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد بھارتی فوج کے مظالم سے تنگ آ کر سرحد عبور کر چکی ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفرآباد کشمیری مہاجرین کے سب سے بڑے کیمپ کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ کشمیری مہاجرین کے احوال اور جہادِ کشمیر کے بارے میں مظفر آباد سے ایک حساس اور غیور خاتون نے اپنے دو عزیزوں جناب شیخ خورشید انور اور جناب شیخ محمد یوسف کے نام مکتوب میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے اور پاکستانی قوم کو اس سلسلہ میں اس کے فرائض کی طرف توجہ دلائی۔ مکتوب کے چند حصے قارئین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ادارہ)
اس وقت شہر میں کم از کم دس ہزار کشمیری لڑکے فروکش ہیں، ان کے قیام و طعام کا بندوبست بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم ان کے لیے خالی کیے ہوئے ہیں۔ محلوں میں خیمے بھی لگے ہوئے ہیں جہاں عارضی طور پر مجاہدینِ آزادی قیام پذیر ہیں۔ موجودہ حالات میں عوامی تعاون ہی بہترین حکمتِ عملی ہے۔ حکومت جتنا کر رہی ہے اتنا ہی مناسب ہے۔ ہم نے پاکستان کی ان شاء اللہ تکمیل بھی کرنی ہے اور پاکستان کو بچانا بھی ہے۔ اہلِ کشمیر پاکستان کے سچے عاشق ہیں۔ اب وہ اہلِ پاکستان کو اپنی آزادی کے لیے کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے بھارت کی گردن پکڑی ہوئی ہے۔ اگر اس نے جھلّا کر پاکستان پر حملہ کیا تو ہم ایک ایک کر کے نثار ہو جائیں گے اور بھارت کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔
آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نوعمر مجاہدین کی اپنی خاص رحمت سے مدد فرما رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے رب نے حضرت محمد مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت کو قبول فرما لیا ہے اور گنہگار امتیوں کو ان کی دعاؤں کے سائے میں لے لیا ہے۔ گذشتہ ماہ ۴۴ لڑکوں کا قافلہ جن کی عمریں ۱۵ سے ۲۴ سال کے درمیان تھیں برفانی پہاڑ عبور کرتا ہوا سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ان کی نظریں بھارتی فوجیوں پر پڑی، یہ لوگ برفباری میں محفوظ ہوتے ہیں لیکن یک لخت موسم صاف ہو گیا اور بھارتیوں کے سٹارز چمکتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ان کے گروپ لیڈر نے مجھے بتایا کہ موت کو سامنے دیکھ کر ہم نے میدانِ بدر کی دعا دہرائی کہ اے اللہ! اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں دشمن سے نجات بخش۔ عین اسی وقت دھند چھا گئی اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے تائید غیبی سمجھ کر رفتار دگنی کر دی۔ ابھی ایک پہاڑ پر چڑھنا باقی تھا، ہمارے حلق خشک ہو گئے اور زبانیں موٹی ہو گئیں۔ سب نے اپنے جوتوں میں پگھلی ہوئی برف سے لب تر کیے۔ سب کے پاؤں snow bits سے زخمی تھے لیکن ہم بڑھتے چلے گئے۔ ڈھائی گھنٹے دھند ہمارے اوپر سایہ فگن رہی اور جب ہم سرحد کے قریب پہنچے تو دھوپ نکل اچانک ہمیں فوجیوں کے سٹارز پھر چمکتے ہوئے دکھائی دیے۔ غالباً ہم بھٹک کر پکٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم اپنے سر بازوؤں میں چھپا کر الٹے لیٹ گئے تاکہ شہادت کی صورت میں ہمارے والدین ہمارے چہرے پہچان سکیں۔ اتنے میں فوجی بھاگتے ہوئے ہمارے قریب آئے اور جنت کی سی آواز آئی السلام علیکم Boys! You are welcome to Azad Kashmir
گذشتہ دنوں ڈیڑھ سو لڑکوں کا قافلہ سرحد عبور کر رہا تھا کہ یہ لوگ غلطی سے راستہ بھول کر بھارتی مورچوں پر پہنچ گئے۔ ان میں سترہ لڑکے بھدرواہ سے اباجی کی فیملی سے ہیں۔ بھارتی فوجیوں کو دیکھ کر انہوں نے ’’پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے‘‘۔ بھارتیوں نے سمجھا کہ آزاد کشمیر کے جوشیلے لڑکے پھر کوئی جلوس وغیرہ نکال کر سرحد عبور کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وائرلیس پر پاکستانی آرمی کے میجر کو گالی دے کر کہا کہ تمہارے یہ لاڈلے پھر ادھر آ گئے ہیں انہیں واپس لے جاؤ ورنہ ہم فائر کھول دیں گے، انہوں نے سرحد کو کھیل بنا رکھا ہے۔ ہمارے میجر نے انتہائی منت سے گذارش کی کہ ہم انہیں خود سزا دے لیں گے، آج کل سکولوں کالجوں میں چھٹیاں ہیں اس لیے یہ شرارتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ پاک آرمی کے جوان خود بھارتی مورچوں میں جا کر انہیں بحفاظت لے آئے۔ ہمیں اپنی بے مثال فوج کی دانشمندی اور بہادری پر فخر ہے۔ یہ مومن کی بصیرت اور علیؓ کے جگر سے سرحدوں پر چوکس اور ہر دم مصروف ہیں۔ ۱۱ فروری کو چکوٹھی بارڈر پر مظفر آباد کے لشکروں نے جو چیڑھ کے درخت پر پرچم لگایا تھا پاک فوج نے بھارتیوں کو یہ پرچم اتارنے کی جرأت نہیں کرنے دی کیونکہ یہ ہمارے بچوں نے اپنا خون دے کر لگایا تھا جو اب پوری آب و تاب سے لہرا رہا ہے۔
لبریشن فرنٹ کے کمانڈر انچیف ملک یسین کی خبر تو آپ نے ٹی وی پر سن لی ہو گی، اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ سلامت ہیں اور محفوظ مقام پر مصروفِ جہاد ہیں۔ اول تو چار منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر بچنا ہی محال ہے، پھر سری نگر کی کرفیوز زدہ سڑک پر آرمی کی حفاظت میں ایمبولینس سے فرار اور بھی ناممکن ہے لیکن اس صدی میں ایسا ہوا ہے اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔
میں یہ سب باتیں آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو یقین آجائے کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہمیں پہنچ رہی ہیں۔ پاکستانی قوم دنیا کی منفرد اور بے مثال قوم ہے۔ اگر قیادت قائد اعظم جیسی میسر آجائے تو اس قوم میں دنیا کی امامت کرنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ ۴۲ برس میں جو کچھ اس قوم کے ساتھ سلوک ہوا ہے اگر کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا تو پوری قوم پاگل ہو جاتی لیکن پاکستانیوں کے صبر و ہمت اور استقلال کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سخت جان قوم سے ضرور کوئی خاص کام لینا ہے اسی لیے اس کی آزمائش بھی کڑی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یورپ کے تربیت یافتہ مٹھی بھر خواص کو ہدایت دے اور ان کے دلوں میں رحم و خداخوفی بھر دے، یہ بے حیائی اور بے ایمانی ترک کر کے ملک سے کھیلنا چھوڑ دیں اور انتشار کا راستہ بدل لیں۔ ایک مضبوط اور متحد پاکستان اہلِ کشمیر اور اہلِ افغانستان کا ناقابلِ تسخیر قلعہ ہے بلکہ اسلامی بلاک کے خواب کی تعبیر ہے۔
کیا آپ دس کروڑ پاکستانیوں میں چار کروڑ بھی ایسے نہیں جو اپنے خرچے پر جمع ہو کر اسلام آباد جائیں اور حکمرانوں کی منت کریں کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک آپ میاں نواز شریف، نواب اکبر بگتی اور الطاف حسین کو دل سے تسلیم کر کے انہیں اپنا دوست سمجھنے کا اعلان نہیں کرتے۔ اسی طرح اتنے ہی لوگ میاں نواز شریف، نواب بگتی اور الطاف حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا گھیراؤ کریں کہ آپ وفاقی حکومت کی اطاعت اور تعاون کا اعلان کریں۔ ایک خوبصورت جمہوری طرزِ عمل ہی اب نفرتوں کے زہر کا تریاق بن سکتا ہے۔ عوام کا شعور بیدار ہو تو حکمرانوں میں سیاسی پختگی خود ہی آجاتی ہے۔ بہتر ہے عوام لیڈروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور خود اپنا جمہوری حق استعمال کریں۔ قوم بیدار ہو تو سیاسی کاروبار کی دکانیں خودبخود بند ہو جاتی ہیں۔ ضمیروں کے سودے اور عوامی رائے کی خریدوفروخت تبھی ممکن ہے جب لوگ مایوسیوں کے گرداب میں پھنس جائیں اور اپنی قسمت کے فیصلے خود نہ کر پائیں۔ آپ لیڈروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر خود موج در موج قافلہ در قافلہ اٹھیں اور حکمرانوں کو باور کرائیں کہ انہیں امریکی سفیرمسٹر رابرٹ اوکلے کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بجائے آپ کے سامنے اپنا عہد نبھانا ہے اور ملک کے مفادات کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وقت اللہ کا خوف اور اس کے احکامات کی پابندی کے علاوہ قومی جرأت و غیرت ہی ہماری آئندہ نسلوں کی آزادی اور سلامتی کی ضامن بن سکتی ہے۔ اپنا انفرادی اور مجموعی فرض ادا کریں۔
مثیلِ موسٰی کون ہے؟
اونٹ کے حوالے سے ایک دلچسپ بحث
محمد یاسین عابد
کراچی سے مبشر انجیل عبد اللہ مسیح نے سیالکوٹ کے پادری برکت اے خان کا رسالہ بعنوان ’’کون مثیلِ موسٰیؑ ہے‘‘ بھیجا جسے پڑھ کر پادری صاحب کی کج فہمی اور علم و عقل کے دیوالیہ پن سے آگاہی ہوئی۔ چنانچہ ص ۴۹ پر لکھتے ہیں:
’’کتابِ مقدس کے خداوند نے جن چوپایوں میں سے چار جانور حرام قرار دیے بزرگ موسٰی نے ان کی بابت توریت شریف میں لکھا ہے: تم ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور سافان کو نہ کھانا کیونکہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں‘‘۔
خان صاحب مزید لکھتے ہیں:
’’مثیلِ موسٰی کے وکلاء کو چاہیئے کہ وہ ثابت کریں کہ مثیلِ موسٰی نے بھی ان چاروں جانوروں کو ناپاک اور حرام قرار دیا تھا اور ان کی لاشوں کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے۔‘‘
صفحہ ۵۰ پر لکھا ہے:
’’پس جو شخص کسی حرام جانور کو حلال اور حلال جانور کو حرام قرار دیتا ہے وہ مثیلِ موسٰی نہیں ہو سکتا۔‘‘
جواباً عرض ہے کہ بائبل استثناء ۶:۱۴ میں ہے کہ
’’چوپایوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور جگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو۔‘‘
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اونٹ اس معیار پر پوتا اترتا ہے یا نہیں؟ یعنی (۱) جگالی کرنا (۲) پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہونا۔
(۱) اونٹ جگالی کرتا ہے
اونٹ کے جگالی کرنے کا کسی کو بھی انکار نہیں۔ خود بائبل کا بیان ہے کہ ’’اونٹ کو کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے‘‘ (احبار ۴:۱۱)۔ یعنی اونٹ کی جگالی پر مزید بحث کی چنداں ضرورت نہیں۔
(۲) اونٹ کے پاؤں
یہ امر روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ اونٹ کے کُھر (پاؤں) چرے ہوئے ہوتے ہیں۔ راقم الحروف نے خود کئی عیسائیوں کو ساتھ لے کر اونٹ کے پاؤں دکھائے تو ان کی بے بسی دیدنی تھی۔ بعض نے کہا کہ اونٹ کے تو صرف کھر چرے ہوئے ہیں نہ کہ پاؤں کا گوشت۔ جواباً عرض ہے کہ بائبل نے بھی کھروں کا چرا ہوا ہونا ہی مشروط ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو استثناء ۶:۱۴ کی عبارت گورمکھی بائبل سے:
’’اتے پسوأں وچوں ہر اک پسو جہدے کھر پاٹے ہوئے ارتھات کھراں دے دو وکھو وکھ حصے ہون اتے اگالی کرن والا ہو وے۔‘‘
ثابت ہوا کہ پاؤں کا گوشت نہیں بلکہ کھروں کا چرا ہوا ہونا مشروط ہے۔ گائے، بھینس اور بکرے کے بھی کھر ہی چرے ہوئے ہوتے ہیں نہ کہ پاؤں کا گوشت۔ البتہ پاؤں کے درمیان گوشت میں بھی ہلکی سی گہرائی ہوتی ہے جو کہ اونٹ کے پاؤں میں بھی موجود ہے، جبکہ کھر علیحدہ علیحدہ دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ یعنی اونٹ دونوں معیاروں پر پوتا اترتا ہے، جگالی بھی کرتا ہے اور اس کے کھر بھی چرے ہوئے ہیں۔ قارئین استثناء ۱۴: ۷۔۸ کے مذکورہ حوالہ کو پڑھ کر ’’بائبل مقدس کے خدا‘‘ کی علمیت کو داد دیں۔
مثیلِ موسٰی
واضح ہو کہ کتاب استثناء ۱۸:۱۸ میں موعود مثیلِ موسٰی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جبکہ عیسائیوں کے نزدیک وہ مثیل موسٰی بنی یسوع ہیں ۔۔۔ اب ہم پادری صاحب کا اعتراض لیتے ہیں جو کہ انہوں نے مسلمانوں پر کیا ہے کہ ’’وہ ثابت کریں کہ مثیلِ موسٰی نے بھی ان چاروں جانوروں کو ناپاک اور حرام قرار دیا تھا اور ان کی لاشوں کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا‘‘۔ پادری صاحب! ’’خدا اور بزرگ موسٰی‘‘ کے قرار دیے ہوئے نہ صرف ان چاروں بلکہ تمام حرام جانوروں کو مسیحیوں کے ’’مثیلِ موسٰی یسوع‘‘ نے پاک ٹھہرایا ہے۔ دیکھو مرقس ۱۹:۷)۔ موجودہ مسیحیت کے بانی پولس کا قول ہے
’’جو کچھ قصابوں کی دکانوں پر بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو‘‘۔ (۱۔ کرنتھیوں ۱۰: ۲۵۔۲۷)
مسیحیوں کے مثیلِ موسٰی نے ان چاروں جانوروں کو کیا ہی خوب حرام اور ناپاک ٹھہرایا تھا جس کا مطالبہ مسلمانوں کے مثیلِ موسٰی سے کیا جا رہا ہے، یا للعجب! پادری صاحب! گلے میں لٹکی ہوئی صلیب پر ہاتھ رکھ کر کہیئے کیا اب بھی مسیح کو مثیلِ موسٰی مانتے ہو؟ جبکہ خود آپ کا ہی قول ہے ’’پس جو شخص کسی حرام جانور کو حلال اور حلال جانور کو حرام قرار دیتا ہے وہ مثیلِ موسٰی نہیں ہو سکتا‘‘۔ (کون مثیل موسٰی ہے ۔ ص ۵۰)
نہ علم نہ عقل نہ فہم نہ شعور
انہیں دیکھو کہ نازاں کس بات پہ ہیں
نو سالہ ماں
حافظ محمد اقبال رنگونی
ترکی میں ایک نو سالہ لڑکی نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے۔ نو عمر ماں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ زچہ و بچہ ٹھیک ہیں۔ اس لڑکی نے مغربی شہر افیاں میں آپریشن کے ذریعے لڑکے کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک انٹرنیشنل میڈیکل لٹریچر کی لسٹ کا تعلق ہے دنیا کی نو عمر ترین ماں کی عمر پانچ برس ہے، تاہم ترکی کے ریکارڈ کے مطابق اس سے قبل ملک کی نو عمر ماں کی عمر بارہ سال تھی۔ لڑکی کو جب ہسپتال لایا گیا تو وہ آٹھ ماہ کی حاملہ تھی۔ (جنگ لندن ۔ ۱۶ مارچ ۱۹۹۰ء)
قارئین کرام نے پہلے بھی یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ ماریلا ایلا نے نو سال کی عمر میں (جنگ ۔ ۱۰ اپریل ۱۹۸۶ء) اور مارتھا نے بھی نو سال کی عمر میں لڑکی کو جنم دیا تھا (ملت لندن ۔ ۲۱ جنوری ۱۹۸۹ء) اور مذکورہ خبر میں بھی یہ ہی ہے، پھر اس میں ’’نو عمر ترین ماں کی عمر‘‘ بھی پیشِ نظر رہے۔ یوں تو ماریا، مارتھا اور مذکورہ لڑکی کا دنیا کی کم سن ماں بن جانا ایک عجوبہ سے کم نہیں اور کئی لوگ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن یہ واقعہ خواہ کتنا ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو چونکہ وجود میں آ چکا ہے اس لیے ہر خاص و عام، دانشور و مفکر اس کی سچائی و اصلیت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور کسی کی زبان پر یہ نہیں آتا کہ یہ کیونکر اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نو سالہ لڑکی صحت مند بچے کو جنم دے دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے یہی عاقل و دانشور، مفکر و محقق کتبِ احادیث میں جب یہ پڑھتے ہیں کہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجھا وھی بنت ست سنین و ادخلت علیہ وھی تسع و مکثت عندہ تسعا (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۷۱)
(ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے ساتھ) نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا جب آپؓ چھ سال کی تھیں اور جب آپؓ کی رخصتی ہوئی تو آپؓ نو سال کی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نو سال رہیں)۔
تو ہمارے یہ دانشور و مفکر نہ صرف حضراتِ محدثین کو برا بھلا کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں بلکہ خود حدیث پاک پر سے بھی بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کافی حد مصروفِ جہاد ہو جاتے ہیں حالانکہ نو دس سال کی عمر میں شادی کا ہونا کوئی معیوب نہیں۔ خود بانیٔ پاکستان جناب محمد علی جناح صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ
’’نو عمر جناح لگ بھگ ۱۵ سال کے تھے اور دلہن ۹۔۱۰ سال کی‘‘۔ (جنگ لندن ۔ ۳۱ مارچ ۱۹۹۰ء)
سو امر واقع یہ ہے کہ صحیح البخاری کی مذکورہ روایت جعلی اور موضوع نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین و محدثین فقہاء کرامؒ نے اس روایت کی روشنی میں بہت سے مسائل و احکام اخذ کیے جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان حضرات گرامی قدر کے نزدیک یہ روایت صحیح اور مبنی بر حقیقت ہے۔ لیکن برا ہو عقل کے ترازو پر ہر چیز تولنے والوں کا کہ انہوں نے جہاں اور بہت سے عقائد و مسائل پر طعن و تشنیع کے نشتر چبھوئے انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ ان دانشوروں نے اس روایت کے انکار کے لیے یہ مفروضہ قائم کر دیا کہ نو سالہ لڑکی بالغ اور ماں کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن جب یہی دانشور اخبارات کی زبانی اور تصاویر کی روشنی میں نو سالہ لڑکی کے نہ صرف بالغ ہونے بلکہ صحتمند بچے کو جنم دے کر ماں بن جانے کی خبر پڑھتے ہیں تو اسے تسلیم کرنے میں انہیں ذرا بھی جھجھک نہیں ہوتی۔ ’’یوں ہو سکتا ہے‘‘ کہہ کر اس کا برملا اعتراف کر لیتے ہیں، کسی قسم کا کوئی اشکال کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ نہ اخباری رپورٹوں کو کوسا جاتا ہے نہ مصوروں کو برا کہا جاتا ہے۔ مگر جب یہی بلکہ اس سے کم بات اگر کسی حدیث میں پڑھتے ہیں تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، جی بھر کر گالیاں دی جاتی ہیں، حدیث کی اصلاح کا مشورہ دیا جاتا ہے، عجمی سازش کی رٹ لگائی جاتی ہے، ملا اور ملائیت کے خلاف ایک طوفانِ بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے۔
آخر اس انکار کا مقصد کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ اخبار کی خبر بلا چون و چرا مان لی جائے اور کتبِ احادیث کی تکذیب کر دی جائے؟ کیا اس کا صاف مقصد یہ نہیں کہ اہلِ اسلام کے قلوب سے احادیث اور محدثین کی عظمت و وقعت گرا دی جائے۔ مسائل و احکام میں من مانی کی اجازت دی جائے۔ اور قرآن کی تشریح میں ہر شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ سوچئے اس کا انجام کیا ہو گا؟ اللہ سب کو عقلِ سلیم اور قلبِ صحیح نصیب فرما دے، آمین۔
آپ نے پوچھا
ادارہ
حضرت سعد بن عبادہؓ اور بیعت سیدنا صدیق اکبرؓ
سوال: عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور پھر آخر دم تک اپنے اس انکار پر قائم رہے تھے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ (محمد معاویہ۔ کراچی)
جواب: جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصارِ مدینہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے جانشینِ رسولؐ کے طور پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا فیصلہ کیا۔ بیعت کی تیاری ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے صورتحال کو تدبر کے ساتھ سنبھال لیا۔ چنانچہ بحث و تمحیص کے بعد بالآخر حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ منتخب کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا اور تمام حاضرین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ کی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہؓ نے بیعت سے انکار کر دیا تھا لیکن یہ روایات درست نہیں ہیں کیونکہ مشہور مؤرخ طبریؒ نے جہاں انکار کی روایات نقل کی ہیں وہاں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی بیان کیے ہیں ’’فتتابع القوم و بایع سعد‘‘ کہ حاضرین نے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر لگاتار بیعت کی اور سعدؓ نے بھی بیعت کی۔
اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ مسند احمد میں سند صحیح کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکرؓ نے اپنے خطاب کے دوران جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا حوالہ دیا کہ ’’الائمۃ من قریش‘‘ حکمران قریش میں سے ہوں گے تو حضرت سعد بن عبادہؓ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا ’’فانتم الامراء و نحن الوزراء‘‘ پس تم امیر ہو گے اور ہم تمہارے وزیر ہوں گے۔ اس لیے بیعت صدیق اکبرؓ سے حضرت سعد بن عبادہؓ کے انکار کی روایات درست نہیں ہیں اور صحیح بات یہی ہے کہ دوسرے صحابہ کرامؓ کے ساتھ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔
سرسید احمد خان اور جہادِ آزادی
سوال: ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی میں سرسید احمد خان کا کردار کیا تھا؟ (حافظ محمد علی صدیقی ۔ لیہ)
جواب: ۱۸۵۷ء میں سرسید احمد خاں ضلع میرٹھ میں سرکاری ملازم تھے اور انہوں نے جہادِ آزادی کے دوران مسلمانوں کے خلاف انگریزی حکومت کا دل کھول کر ساتھ دیا۔ سرسید احمد خان نے ۱۸۵۷ء کے معرکۂ حریت پر ’’اسبابِ بغاوتِ ہند‘‘ کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں اپنے بارے میں ایک انگریز افسر مسٹر جان کری کرافٹ کے مندرجہ ذیل ریمارکس نقل کیے:
’’تم ایسے نمک حلال نوکر ہو کہ تم نے اس نازک وقت میں بھی سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور باوجود کہ بجنور کے ضلع میں ہندو اور مسلمانوں میں کمال عداوت تھی اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی حکومت کو مقابلہ کر کے اٹھایا تھا، جب ہم نے تم کو اور رحمت خان صاحب بہادر ڈپٹی کلکٹر کو ضلع سپرد کرنا چاہا تو تمہاری نیک خصلت، اچھے چال چلن اور نہایت طرفداری سرکار کے سبب ہندوؤں نے، جو بڑے رئیس اور ضلع میں نامی چودھری تھے، سب نے کمالِ خوشی اور نہایت آرزو سے تم مسلمانوں کا اپنے پر حاکم بنانا قبول کیا، بلکہ درخواست کی کہ تم ہی سب ہندؤں پر ضلع میں حاکم بنائے جاؤ۔ اور سرکار نے بھی ایسے وقت میں تم کو اپنا خیرخواہ اور نمک حلال نوکر جان کر کمال اعتماد سے سارے ضلع کی حکومت تم کو سپرد کی اور تم اسی طرح وفادار اور نمک حلال نوکر سرکار کے رہے۔ اس کے صلے میں اگر تمہاری ایک تصویر بنا کر پشت ہا پشت کی یادگاری اور تمہاری اولاد کی عزت اور فخر کو رکھی جاوے تو بھی کم ہے۔‘‘ (ص ۱۹۲)
یہ تو انگریز حکام کے تاثرات ہیں اور جہاد ۱۸۵۷ء کے بارے میں جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، مولانا سرفراز علی شہید، مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا عبد القادر لدھیانوی، جنرل بخت خان اور سردار احمد خان کھرل رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے مجاہدین شریک ہوئے، سرسید احمد خان کے اپنے تاثرات کیا تھے وہ خود سرسید احمد خان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے:
’’غور کرنا چاہیئے کہ اس زمانہ میں جن لوگوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا ایسے خراب اور بدرویہ اور بداطوار آدمی تھے کہ بخدا شراب نوشی، تماش بینی اور ناچ رنگ دیکھنے کے کچھ دریغ ان کا نہ تھا۔ یہ کیونکہ پیشوا اور مقتدا جہاد کے کہے جا سکتے تھے۔ اس ہنگامہ میں کوئی بات بھی مذہب کے مطابق نہ ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب جو امانت تھا اس میں خیانت کرنا، ملازمین سے نمک حرامی کرنی، مذہب کی رو سے درست نہ تھی۔ صریح ظاہر ہے کہ بے گناہوں کا قتل علی الخصوص عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا مذہب کے موجب گناہِ عظیم تھا۔ پھر یہ ہنگامۂ غدر کیونکر جہاد ہو سکتا تھا؟ ہاں البتہ چند بدذاتوں نے دنیا کی طمع اور اپنی منفعت اور اپنے خیالات پورا کرنے اور جاہلوں کو بہکانے کو اور اپنے ساتھ جمعیت کرنے کو جہاد کا نام لے دیا۔ پھر یہ بات بھی مفسدوں کی حرامزدگیوں میں سے ایک حرامزدگی تھی، نہ واقع میں جہاد‘‘۔ (ص ۹۳)
نشہ کی حالت میں مرنے والے کا جنازہ
سوال: جو شخص نشہ کی حالت میں مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا چاہیئے یا نہیں؟ (عبد اللطیف ۔ گوجرانوالہ)
جواب: نشہ کرنا خواہ وہ کسی چیز سے ہو حرام ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ’’کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ‘‘ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نشہ کرنے والا شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب اور فاسق ہے لیکن اس سے کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اسی حالت میں مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ اسی نوعیت کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امداد الاحکام جلد اول ص ۲۵ میں لکھتے ہیں کہ:
’’شراب کے نشہ میں مرنے سے ایمان زائل نہیں ہوتا، ایمان کفر سے زائل ہوتا ہے، اور یہ فعل کفر نہیں بلکہ معصیت کبیرہ ہے۔ پس یہ شخص مسلمان ہے اس کی نمااز جنازہ پڑھی جائے۔ البتہ زجرو توبیخ کے لیے عالم مقتدا اور امام جامع مسجد اس کی نماز نہ پڑھے، عام مسلمان نماز پڑھ کر دفن کر دیں۔ اگر بدونِ نماز کے دفن کیا گیا تو سب گنہگار ہوں گے۔‘‘
گنٹھیا ۔ جوڑوں کا درد یا وجع المفاصل
حکیم محمد عمران مغل
عربی زبان میں جوڑوں کے درد کو وجع المفاصل کہا جاتا ہے۔ اگر یہ جوڑ اپنا اپنا کام ٹھیک طرح سے کرتے رہیں تو انسانی زندگی نہایت پرسکون گزر سکتی ہے۔ صحت کا دارومدار بڑی حد تک جوڑوں کا ہی رہینِ منت ہے۔ اسی لیے امتِ مسلمہ کو ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ شکریہ ادا کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ خدانخواستہ اگر جوانی میں ہی اعصاب اور جوڑ کسی وجہ سے متاثر ہو جائیں تو پھر آپ جوان ہو کر بھی بوڑھے ہیں۔ جن حضرات کے اعصاب (پٹھے) اور جوڑ تندرست رہیں گے ان کی عمریں بھی زیادہ ہوں گی۔
طبِ اسلامی اور یونانی میں انسانی جوڑوں کے دردوں کو الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً گھٹنوں کے درد کو وجع المفاصل، انگلیوں کے جوڑوں کے درد کو درد نقرس، سرین کے درد کو وجع الورک، پھر سرین سے شروع ہو کر نیچے ٹخنے تک ہونے والے درد کو عرق النساء کہا جاتا ہے۔ مطلق گھٹنے کے درد کو وجع الرکبہ بھی کہتے ہیں۔ حکماء مقتدمین اور طبِ اسلامی کے اصولوں کے مطابق اس مرض کے پانچ بڑے اسباب ہیں مگر ان پانچ اسباب کو سمجھنے کے لیے صرف ان دو حالتوں کو ہی سمجھ لینا کافی ہے:
(۱) وجع المفاصل حار
یعنی پہلے تیز بخار کے ساتھ جوڑ متورم ہو کر شدید درد پیدا ہو گا خصوصاً گھٹنے اور انگلیوں کا درد تڑپائے گا۔ وجہ غلبہ خون یا غلبہ صفرا ہو گا اور یہ غلبہ شراب نوشی، گوشت خوری، ہر وقت پرشکم رہنا، ورزش کا فقدان، موروثی استعداد، مٹھائی کا زیادہ استعمال کرنا، بارش میں اکثر بھیگتے رہنا، نمدار جگہوں پر بود و باش اختیار کرنا، بھیگے کپڑے دیر تک پہنے رکھنا، فساد ہضم، موسم کی تبدیلی، سخت جسمانی محنت، کسی ضرب یا چوٹ کا لگنا، متعدی امراض کا حملہ، ایسی جگہ رہنا جہاں یکایک ہوا مرطوب اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے مثلاً ایئرکنڈیشن کمرے۔ مستورات کا حیض بند ہو جانا یا اولاد اس کثرت سے پیدا ہونا کہ پہلے بچے کا دودھ کا زمانہ ختم نہ ہوا ہو وغیرہ وغیرہ۔
وجع المفاصل حال اگر کافی عرصے تک رہے تو اس سے غلافِ قلب میں ورم پیدا ہو کر دل کے امراض کا مزید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جدید اصطلاح میں بورک ایسڈ کا جمع ہونا بھی دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ مادہ جسے گردے خون وغیرہ سے صاف نہ کر سکیں تو وہ جوڑوں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ سہولت اور آسانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر درد زیادہ اور تڑپا دینے والا ہو اور بخار بھی ہو تو درد کی جگہ سرخ اور رگیں خون سے پر ہوں گی تو اب غلبہ خون پر ہو گا۔ اس لیے خون کی خرابی اور خون کے نقائص کی طرف توجہ دیں۔ اگر درد شدید مگر جلن کے ساتھ ہو، بخار بھی لرزہ کے ساتھ بار بار لوٹے اور پھر چڑھے، منہ کا ذائقہ تلخ ہو تو غلبہ صفرا ہو گا۔
(۲) وجع المفاصل بارد
اس کی وجوہات جسم میں بلغم کی زیادتی یا خلط سودا کی زیادتی (یاد رہے کہ علم طب میں چار اخلاط کا خصوصیت سے ذکر ہے)، یا غلبہ ریاح، یا مذکورہ بالا اخلاط میں سے کسی خلط کا احتراق، یا وہ خلط اپنی تعریف پہ پوری نہ اتر سکے وغیرہ۔ وجع المفاصل بارد تقریباً پوری عمر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ درد سردی کے موسم میں بہ نسبت گرمی کے زیادہ ستاتا ہے اور پھر سردی کی راتوں کو تو اس کا مریض تارے گنتا رہتا ہے۔ البتہ دن کو سورج کی تپش سے سکون ملتا ہے۔
ایک درد اور بھی ہے جسے عرق النسا کہتے ہیں۔ عرق النسا ایک رگ کا نام ہے جو سرین کے نیچے سے نکل کر ران اور پنڈلی کی پچھلی جانب سے ٹخنے تک آتی ہے۔ یہ درد کبھی ایک ٹانگ کبھی دونوں میں ہوتا ہے، اس کی وجہ (نقرس) یعنی چھوٹے جوڑوں کا درد، یا وجع المفاصل کا پہلے سے ہونا، یا اس کا مریض رہنا، یا فساد خون، یا بدن میں آتشک کا مادہ (یاد رہے آتشک اور سوزاک موروثی امراض ہیں، یہ نسل در نسل چلتی ہیں اور آٹھویں، دسویں، بارہویں تک کی پشت کو بھی متاثر کر سکتی ہیں)، سرد جگہ اٹھنا بیٹھنا، قبض رہنا، پشت کے مہرے متاثر ہونا، یا پیڑو کا ماؤف ہونا وغیرہ وغیرہ۰
پرہیز اور علاج
چاول، گوشت ہر قسم، ماش کی دال، اروی مٹھائی اور میدہ کی بنی ہوئی ہر قسم کی اشیاء، ایئرکنڈیشن، برف کا استعمال، آئس کریم ہر قسم کی، رنگ برنگی بوتلیں اور شربت، برف میں لگی ہوئی بوتلیں اور تمام مصنوعی خوردنی اشیاء سے پرہیز کر کے کچھ دن اصل اور فطری زندگی کو اپنائیں اور قدرت خدا کا مشاہدہ کریں۔ ان شاء اللہ سو فیصد افاقہ ہو گا۔ جدید سائنس نے دنیا کو اتنا آرام دہ اور حسین بنا دیا ہے کہ ہر ایک اس کا دلدادہ ہو کر اپنی صحت برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی حقیقت تو اسلاف نے یہ فرمائی تھی:
بڑی کافرہ سارحہ ہے یہ دنیا
بباطن خبیثہ بظاہر حسینہ
(۱) کسی بھی دواخانہ کی معمون سورنجان لے کر حسب ہدایت کھائیں، سو فیصد افاقہ ہو گا ان شاء اللہ۔
(۲) مجرب اور کم خرچ نسخہ: چھوٹی کالی بڑ کے پورے چار ٹکڑے کریں۔ کم یا زیادہ نہ ہوں، شرط ہے۔ چھ ماثریہ ٹکڑے رات ضروریات سے فارغ ہو کر منہ میں ڈال کر تازہ پانی سے نگل لیں اور چبانا بالکل نہیں، یہ بھی شرط ہے۔ پھر صبح سویرے اٹھ کر ایک پاؤ دودھ بکری یا گائے کا کچا پی لیں۔ پرانا درد ایک ماہ میں اور عام درد ایک ہفتہ میں بالکل ختم۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’نبویؐ لیل و نہار‘‘
تالیف: امام احمد بن شعیب النسائیؒ (المتوفی ۳۰۳ھ)
ترجمہ: مولانا محمد اشرف، فاضل نصرۃ العلوم گوجرانوالہ
خوبصورت و مضبوط جلد، کتابت و طباعت عمدہ ۔ صفحات ۶۷۰ قیمت ۱۳۰ روپے
ملنے کا پتہ: مکتبہ حسینیہ، قذافی روڈ، گرجاکھ، گوجرانوالہ
یہ کتاب امام نسائیؒ کی معروف تصنیف ’’عمل الیوم واللیلۃ‘‘ کا اردو ترجمہ ہے جس میں امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اذکار اور روزمرہ ضروریات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات کو جمع فرما دیا ہے۔ امام نسائیؒ امتِ مسلمہ کے عظیم محدثین میں سے ہیں جن کی شہرۂ آفاق تصنیف ’’سنن نسائی‘‘ کو حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ سب سے بڑی اور مستند کتابوں (صحاح ستہ) میں شمولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور امام نسائیؒ جیسے جلیل القدر محدث کا نام سامنے آ جانے کے بعد کتاب کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔
مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے فاضل استاذ مولانا محمد اشرف نے انتہائی عرق ریزی کے ساتھ اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا سید نفیس شاہ صاحب مدظلہ العالی کی تجویز پر اس کا نام ’’نبویؐ لیل و نہار‘‘ رکھا گیا ہے۔ کتاب عرصہ سے نایاب تھی، مولانا محمد اشرف علمی حلقوں کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ’’عمل الیوم واللیلۃ‘‘ کا اردو ترجمہ اصل متن کے ساتھ شائع کر کے اہلِ علم کو اس سے استفادہ کا موقع فراہم کیا ہے۔
’’تقویٰ باطنی کمال کا معیار‘‘
افادات: شیخ الاسلام مولانا محمد عبد اللہ درخواستی
مرتب: مولانا فضل الرحمٰن درخواستی
ناشر: جامعہ مخزن العلوم، عیدگاہ، خانپور، ضلع رحیم یار خان
حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواستی دامت برکاتہم ہمارے دور کی ان برگزیدہ علمی اور روحانی شخصیات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کے متنوع کمالات سے نوازا ہے اور انہیں مخلوقِ خدا کے ایک بڑے حصہ کی ہدایت اور راہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت درخواستی مدظلہ نے درس و تدریس، وعظ و نصیحت، ذکرِ الٰہی اور علماء کی سیاسی قیادت کے محاذوں پر پون صدی سے زیادہ عرصہ تک متحرک کردار ادا کیا ہے اور اب بھی بڑھاپے، بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود اس سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا وعظ و خطاب کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے جس میں جذب کا پہلو غالب ہوتا ہے اور وعظ و نصیحت کے بے باک انداز پر جذب کا یہ پرتو ہی ان کی امتیازی خصوصیت ہے جو ان کے عقیدت مندوں کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے اور ان کے سامعین گھنٹوں ان کے سامنے محوِ کیف رہتے ہیں۔
زیرِنظر رسالہ حضرت درخواستی مدظلہ کے ایک خطاب پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے تقوٰی کی حقیقت، متقین کی صفات، اور تقوٰی کے تقاضوں پر اپنے مخصوص انداز میں روشنی ڈالی ہے اور ان کے ہونہار فرزند مولانا فضل الرحمٰن درخواستی نے اسے مرتب کر کے انتہائی عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ رنگین آرٹ پیپر پر شائع کیا ہے۔ رسالہ کے صفحات ۳۸ ہیں اور جامعہ مخزن العلوم خانپور کے علاوہ البدر جنرل سٹور بازار سیدنگری گوجرانوالہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
’’سوانح حیات مولانا غلام رسولؒ‘‘
مصنف: مولانا عبد القادر
ناشر: فضل بکڈپو، اردو بازار، گوجرانوالہ
صفحات ۱۸۰ قیمت ۱۸ روپے
قلعہ میاں سنگھ ضلع گوجرانوالہ میں ایک باکمال بزرگ مولانا غلام رسولؒ گزرے ہیں جن کا تعلق اہلحدیث مکتب فکر سے تھا لیکن روایتی انداز سے ہٹ کر وہ معتدل اور صوفی مزاج بزرگ تھے۔ حدیث میں حضرت میاں نذیر حسین دہلویؒ اور حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلویؒ کے شاگرد تھے۔ حق گو عالم تھے۔ ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی میں شرکت کے الزام میں گرفتاری اور نظربندی کے مراحل سے بھی گزرے۔ صاحبِ نسبت تھے اور ان کی کرامات کا بھی دور دور تک شہرہ تھا۔ پنجابی، اردو اور فارسی کے شاعر تھے اور اپنے دور کے کی مقبولِ خلائق شخصیات میں سے تھے۔ ان کے فرزند مولانا عبد القادرؒ نے اپنے والدِ محترمؒ کے حالات کو اس کتابچہ میں جمع کیا ہے۔ اس قسم کے بزرگوں کے حالاتِ زندگی کا مطالعہ اصلاحِ نفس اور عبرت و نصیحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔
’’زعیمِ ملت مولانا ہزارویؒ‘‘
مرتب: مولانا محمد سعید الرحمٰن علوی
صفحات ۲۰ کتابت و طباعت معیاری
ملنے کا پتہ: مکتبہ حنفیہ، اردو بازار، گوجرانوالہ
بزم شیخ الہند گوجرانوالہ نے گذشتہ سال مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں مولانا محمد سعید الرحمٰن علوی نے اپنے مخصوص انداز میں ایک مضمون پڑھا، یہ مضمون ان کی نظرثانی کے بعد زیرنظر رسالہ کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔
برصغیر کی تحریکِ آزادی اور پاکستان میں نفاذِ اسلام کی جدوجہد میں مولانا غلام غوث ہزارویؒ ایک زندہ اور متحرک کردار کا نام ہے۔ اس بے لوث اور فعال کردار کے مختلف زاویوں کو صحیح طور پر نئی نسل کے سامنے لانا نہ صرف ان کا بلکہ نئی نسل کا بھی حق ہے، اور مولانا علوی نے اپنے مضمون میں ایک حد تک کوشش بھی کی ہے لیکن مضمون پر ان کا مخصوص ناقدانہ رنگ غالب ہے، اگر اس کے ساتھ وہ معلوماتی مواد کا توازن بھی قائم کر لیتے تو مضمون کی افادیت بڑھ جاتی۔ بہرحال مولانا علوی اور بزم شیخ الہند تبریک و تحسین کے مستحق ہیں کہ اس نفسانفسی کے دور میں جبکہ بزرگوں کو بھول جانے کی روایت فیشن کا رنگ اختیار کر چکی ہے، انہوں نے مولانا ہزارویؒ کی یاد کو تازہ رکھنے کی کوئی صورت تو نکالی۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔
مکان کیسا ہونا چاہیئے؟
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
مسکن کے سلسلہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی کو گرمی سردی کی شدت اور چوروں کے حملوں سے بچا سکے اور گھر والوں اور ان کے سامان کی حفاظت کر سکے۔ ارتفاقِ منزل کا صحیح مقصود یہی ہے۔ چاہیئے یہ کہ مسکن کی تعمیر میں استحکام کے توغل و تکلف اور اس کے نقش و نگار میں اسرافِ بے جا سے احتراز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکان حد درجہ تنگ بھی نہ ہو۔ بہترین مکان وہ ہے جس کی تعمیر بلا تکلف ہوئی ہو۔ جس میں رہنے والے مناسب طور پر آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ فضا وسیع و عریض ہو، ہوا دار ہو اور اس کی بلندی بھی متوسط درجہ کی ہو۔
مکان ہو یا دیگر ضرورتیں، ان سب کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ پیش آمدہ ضرورتوں کو اس طور سے پورا کیا جائے جو طبعِ سلیم اور رسمِ صالح کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ لیکن بدقسمتی سے بعض لوگ شاندار عمارتیں بنوانے میں ہوائے نفس کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی تعمیر میں نفسانی خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کو مقصود بالذات چیز سمجھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ نہ تو دنیا کی کد و کاوش سے نجات پا سکتے ہیں اور نہ انہیں فتنۂ قبر اور فتنۂ محشر سے نجات مل سکے گی۔ (البدور البازغۃ مترجم ص ۱۲۳)
قرآنِ کریم کے ماننے والوں کا فریضہ
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
ہم پر، جو قرآنِ کریم کو ماننے والے ہیں، قطعی طور سے لازم ہے کہ ہم تمام اقوامِ عالم کے سامنے ثابت کر دیں کہ انسانیت کے ہاتھ میں قرآنِ کریم سے زیادہ درست اور صحیح کوئی پروگرام نہیں۔ پھر ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر ایمان لا چکے ہیں ان کی جماعت کو منظم کیا جائے، خواہ وہ کسی قوم یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہم ان کی کسی اور حیثیت کی طرف نہ دیکھیں بجز قرآن کریم پر ایمان لانے کے۔ پس ایسی جماعت ہی مخالفین پر غالب آئے گی۔ لیکن ان کا غلبہ انتقامی شکل میں نہیں ہو گا بلکہ ہدایت اور ارشاد کے طریق پر ہو گا جیسا کہ والد اپنی اولاد پر غالب ہوتا ہے۔ اب اس نظام کے خلاف جو بھی اٹھ کھڑا ہو گا وہ فنا کر دینے کے قابل ہو گا۔ (الہام الرحمٰن)
دنیا سے ظلم کو دور کیا جائے، چاہے کسی شکل میں ہو۔ اور اسے دور کر کے قرآن کریم کی حکومت پیدا کی جائے۔ مثلاً ہمارے زمانے میں معاشی ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے اور یہاں عدمِ توازن کی وجہ سے عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اکثر لوگ غذا نہ ملنے یا ناقص غذا ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں اور صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے انسانی فرائض ادا نہیں کر رہے اور نہ ادا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ انہیں اس حالت سے نکال کر ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ فکرِ معاش سے نجات پا کر اللہ کی یاد میں لگ سکیں، ہر اس شخص کا فرض ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کو مانتا ہے۔ (جنگِ انقلاب ص ۵۸۳)
مسلمانوں کی قوت کا راز — خلافت
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
اس وقت دنیا میں پچاس کے قریب اسلامی حکومتیں ہیں مگر کوئی بھی اپنی رائے میں آزاد نہیں ہے۔ سب غیر مسلموں کے دستِ نگر ہیں، تمام اہم امور انہی کے مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ جب سے خلافتِ ترکی کا خاتمہ ہوا ہے مسلمانوں کا وقار ختم ہو گیا ہے۔
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نے اپنے خطبہ میں لکھا ہے کہ مصر کا ایک انگریز اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ ہم تہارے خلیفہ سے بہت خائف ہیں، جب کوئی شکایت خلیفہ کے پیش ہوتی ہے وہ اس کے تدارک کی فورًا کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کفار کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر خلافت کی طاقت نہ ہوتی تو ہم مسلمانوں کو بہت ذلیل کرتے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب خلافتِ اسلامیہ بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ اور جب یہ اپنے عروج پر تھی تو کسی کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اب حالات بالکل بدل چکے ہیں اور مسلمان ہر جگہ غیر مسلموں کے تختۂ مشق بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب مسلمان اپنے مشن کو ترک کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ان کو عزت کا کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بجائے اغیار کے مشوروں کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو، سیاسیات ہوں یا اقتصادیات، زراعت ہو یا تجارت، ہر چیز میں غیر مسلم دخیل ہیں۔ حتٰی کہ تہذیب اور فیشن بھی انہی کا اپنا لیا گیا ہے۔ وقار تو ان قوموں کا ہوتا ہے جو اپنے نظریے پر قائم ہوں۔
مسلمان جب تک اپنے مشن پر قائم رہے انہیں دنیا میں عزت و وقار حاصل تھا مگر اب ہم نے غیروں سے مشورے کر کے خود ان کو اپنا رازداں بنا لیا ہے۔ وہ ہمیں اچھا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ہماری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اقوام کے ساتھ دلی دوستی قائم نہیں کرنی چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ’’ھانتم اولآء تحبونھم‘‘ اے ایمان والو! تم تو دوسروں سے محبت کرتے ہو ’’ولا یحبونکم‘‘ مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ تم تو عیسائیوں، یہودیوں، انگریزوں اور امریکنوں کو اپنا رازدار بنا رہے ہو، ان کو مشیر بنا رکھا ہے، ان سے محبت بڑھا رہے ہو، مگر وہ تم سے دلی لگاؤ نہیں رکھتے۔ لہٰذا ان کے ساتھ تمہاری محبت یکطرفہ ہے۔
محبت ہمیشہ جانبین کی طرف سے ہونی چاہیئے۔ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ لہٰذا صرف تمہاری طرف سے یکطرفہ محبت کوئی محبت نہیں، وہ تو اللہ، اس کے رسولؐ اور قرآن پاک کے شدید ترین دشمن ہیں ’’لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین اٰمنوا الیھود‘‘ مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں۔ اس کے بعد مشرکین اور نصارٰی کا نمبر آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صرف تمہاری طرف سے دوستی اور محبت اہلِ اسلام کے لیے لازماً نقصان کا باعث ہو گی۔
جولائی ۱۹۹۰ء
شریعت بل اور تحریک نفاذ شریعت
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
ماہِ رواں کی سترہ تاریخ کو فلیش مین ہوٹل راولپنڈی صدر میں منعقدہ آل پارٹیز نفاذِ شریعت کانفرنس میں ’’شریعت بل‘‘ کو قومی اسمبلی سے منظور کرانے اور سودی نظام کی وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے پورے ملک میں تحریک نفاذ شریعت منظم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
’’آل پارٹیز نفاذِ شریعت کانفرنس‘‘ جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل اور شریعت بل کے محرک سینیٹر مولانا سمیع الحق کی دعوت پر منعقد ہوئی جس سے مولانا عبد الستار خان نیازی، مولانا فضل الرحمان، مولانا محمد اجمل خان، مولانا محمد عبد اللہ، صاحبزادہ حاجی فضل کریم، مولانا معین الدین لکھوی، مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، مولانا ضیاء القاسمی، مولانا قاضی احسان الحق، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، مولانا وصی مظہر ندوی اور دیگر سرکردہ علماء کرام کے علاوہ قومی شخصیات میں سے نوابزادہ نصر اللہ خان، جناب غلام مصطفیٰ جتوئی، میاں محمد نواز شریف، اقبال احمد خان، راجہ محمد ظفر الحق، جناب اعجاز الحق، پروفیسر غفور احمد اور جناب طارق محمود ایم این اے نے بھی خطاب کیا۔
’’شریعت بل‘‘ اس وقت قومی اسمبلی کے حوالے ہو چکا ہے اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور خواجہ طارق رحیم کے ایک بیان کے مطابق اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں زیر بحث آنے والا ہے۔ اس مرحلہ پر ملک کے اہم سیاسی و دینی حلقوں کا یہ اتفاق و اشتراک بلاشبہ ایک نیک فال اور عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی اہل دین نے متحد ہو کر کسی جدوجہد کا آغاز کیا ہے انہیں اہل سیاست کی حمایت بھی حاصل ہوئی ہے اور وہ جدوجہد میں کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئے ہیں۔ اہل دین کا اتحاد ہمارے ملک کے بہت سے مسائل کا حل اور نفاذِ اسلام کی جدوجہد کی کامیابی کی کلید چلا آرہا ہے۔
ہم ’’تحریک نفاذِ شریعت‘‘ کے آغاز کے اس فیصلہ کا خیرمقدم کرتے ہوئے دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت اہل دین کے اتحاد کو ملت کے لیے مبارک کریں اور اسے ملک میں شریعت اسلامیہ کی بالادستی کا ذریعہ بنائیں، آمین یا الہ العالمین۔
انسانی اجتماعیت اور آبادی کا محور
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر نزولِ قرآن کے ہزاروں سالہ دور میں عرب کے خطہ میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی، یہاں پر قبائلی نظام رائج تھا۔ مصر، شام، روم، ایران اور ہندوستان وغیرہ میں تو باقاعدہ حکومتیں تھیں مگر جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مرکزی تنظیم نہیں تھی۔ اس افراتفری اور نفسانفسی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ سال بھر میں چار حرمت والے مہینوں کے دوران لڑائی بند رہتی تھی، قافلے بلا روک ٹوک سفر کر سکتے تھے، خوب تجارت ہوتی تھی اور لوگوں کو امن حاصل ہوتا تھا اور یہ سب کچھ بیت اللہ شریف کے احترام کی وجہ سے ہوتا تھا۔
یہاں پر لوگوں کے قیام سے مراد یہ ہے کہ اس محترم گھر کی وجہ سے لوگ قائم ہو سکتے تھے یعنی اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اگر امن و امان کے یہ چار مہینے بھی لوگوں کو میسر نہ ہوتے تو جنگ و جدال اور لوٹ مار کی وجہ سے ہر قسم کا کاروبار، کھیتی باڑی اور تجارت ٹھپ ہو کر رہ جاتے اور لوگوں کو زندگی گزارنا محال ہو جاتا۔ قیام کا یہ معنی سورۃ نساء میں یوں بیان ہوا ہے ’’ولا توتو السفھاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما‘‘ اپنے مال بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے یہ گزران کا ذریعہ بنائے ہیں۔ بیت اللہ شریف بھی اسی لحاظ سے ذریعہ معاش ہے اور اس کی بدولت لوگ گزر اوقات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حکم ہے ’’وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً‘‘ کہ وہ صاحب استطاعت ہیں تو زندگی بھر میں کم از کم ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا حج کریں۔
جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ اور یہی چیزیں ہیں جن کی بدولت عازمینِ حج و عمرہ کو جسمانی، روحانی، علمی اور اخلاقی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں بھی فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر ’’لیشھدوا منافع لھم‘‘ لوگوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے قیام یعنی گزران کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی طواف اور قربانی ہوتی رہے گی، نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، دنیا بھی قائم رہے گی۔۔۔ اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا قائم نہیں رہے گی۔ سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے ’’ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا‘‘ اللہ تعالیٰ کا اس سرزمین پر سب سے پہلا گھر یہی ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مکہ معظمہ میں تعمیر کیا گیا اور یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے۔
بعض احادیث میں آتا ہے کہ حرم شریف میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیے اور باقی ساٹھ دیگر عبادت گزاروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کی یہ خصوصی رحمتیں ہیں، دیگر مہربانیوں کے علاوہ ہیں۔ انہی کثرتِ فضائل کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ کھینچ کھینچ کر آتے ہیں اور گزران کا ذریعہ بنتے ہیں۔
بیت اللہ شریف ظاہری طور پر بھی پوری کائنات کا مرکز ہے اور روحانی طور پر بھی۔ یہ اہل اسلام کا مرکز ہے، جب تک مسلمان اس کی مرکزیت کو قائم رکھیں گے خود انہیں دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل رہے گی اور جب یہی مرکزیت ٹوٹ گئی تو مسلمان بھی دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ مقامِ افسوس ہے کہ اہلِ اسلام کی یہ مرکزیت ایک عرصہ سے ختم ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں مسلمان ہر مقام پر ذلت کی علامت بن رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح، تکمیلِ اخلاق، روحانیت اور علومِ ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ اسی سرزمین میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاۃ ہوئی۔ قرآن کریم یہیں نازل ہوا۔ اسی بیت اللہ شریف کو ہمیشہ کے لیے نمازوں کا قبلہ مقرر کیا گیا، اسے حج و عمرہ کا مرکز بنایا گیا، لہٰذا یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ اس کی شرف و عزت قربِ قیامت تک قائم رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر حبشہ کا موٹی پنڈلیوں والا ایک ظالم انسان اس پر حملہ آور ہو کر اسے گرا دے گا اور اس کے بعد جلدی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تک کعبہ شریف اور دیگر شعائر اللہ کی عزت و حرمت اور مرکزیت قائم ہے دنیا قائم ہے اور جب یہ نہ رہے گی تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔
خبرِ واحد کی شرعی حیثیت
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
ترتیب و تحریر: حافظ رشید الحق خان عابد
خبرِ واحد اگرچہ عقائد کے باب میں موجبِ علم نہیں لیکن عمل کے باب میں حجت ہے۔ چنانچہ شرح العقائد ص ۱۰۱ میں ہے کہ خبرِ واحد ظن کا فائدہ ہی دے گا بشرطیکہ اصولِ فقہ میں مذکورہ تمام شرائط اس میں موجود ہیں اور ان شرائط کے باوجود بنا بر ظنیت کے اعتقادیات میں اس کا کچھ اعتبار نہیں ہو گا۔ اور تقریباً اسی مفہوم کی عبارات شرح الموافق ص ۷۲۷، المسامرۃ ص ۷۸، اور شرح فقہ اکبر ملا علی ن القاریؒ ص ۶۸ میں بھی موجود ہیں۔ اور نبراس ص ۲۵۰ میں ہے کہ ظن کا اعتبار علمیات میں ہوتا ہے اور ظن کے ساتھ ثابت حکم واجب ہوتا ہے۔
خبرِ واحد کی حجیت پر قرآنِ کریم سے اختصارًا بعض دلائل
پہلی دلیل
حضرت موسٰی علیہ السلام سے خطأً جب ایک اسرائیلی (جس کا نام قاب یا فانون یا فلثیون تھا) قتل ہو گیا اور فرعون کی کابینہ نے حضرت موسٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی تو ’’وَجَاء رَجُلٌ (فرعون کا چچا زاد جس کا نام عند الاکثر حزقیل و عند البعض حبیب یا شمعان اور بعد میں حضرت موسٰی علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا) مِّنْ اَقْصَی الْمَدِیْنَۃِ یَسْعٰی قَالَ یَا مُوْسٰی اِنَّ الْمَلَاَ یَاْتَمِرُوْنَ بِکَ لِیَقْتُلُوْکَ فَاخْرُجْ اِنِّیْ لَکَ مِنَ النَّاصِحِیْنَ‘‘ (القصص ۲۰) حضرت موسٰیؑ نے صرف اس ایک آدمی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے مدین کی طرف روانگی اختیار فرمائی اور ظالم قوم سے نجات پائی۔ اگر ایک آدمی کی بات قابلِ اعتماد نہ ہوتی یا بالفاظِ دیگر اگر خبرِ واحد حجت نہ ہوتی تو حضرت موسٰی علیہ السلام اس پر اعتماد نہ کرتے۔
دوسری دلیل
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ’’فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَۃٍ مِّنْھُمْ طَائِفَۃٌ لِّیَتَفَقَّھُوْا فِی الدِّیْنِ وَلِیُنْذِرُوْا قَوْمَھُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُوْنَ‘‘ (التوبہ ۱۲۲)۔
حضرت مجاہدؒ بن جبیرؒ تابعی فرماتے ہیں کہ طائفۃ کا لفظ ایک سے ہزار تک بولا جاتا ہے اور مسند عبد بن حمید میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے ’’قال الطائفۃ رجل فصاعدًا‘‘ کہ طائفہ کا لفظ ایک پر بھی اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے (درمنشور ص ۲۵۵ ج ۳)۔ اور امام بخاری ص ۱۰۷۶ ج ۲ پر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو بھی طائفہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ارشاد باری تعالٰی ہے ’’وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ اقْتَتَلُوْا (الآیۃ) اگر دو آدمی آپس میں لڑائی کریں تو وہ بھی آیت کے لفظ طائفتان میں داخل ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے ایک ایک امیر کو مختلف جہات میں کیوں بھیجتے؟
اس دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ طائفہ یعنی ایک کی بات دینی اعتبار سے قوم کو عذابِ خداوندی سے ڈرانے کے لیے معتبر اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ خبرِ واحد حجت ہو کیونکہ اگر طائفہ کا اطلاق رجل پر نہ ہو تو دو آدمیوں کی لڑائی میں مصالحت کرانا آیت سے ثابت نہ ہو سکے گا اور امراء کو اکیلے اکیلے بھیجنا بیکار ثابت ہو گا۔
تیسری دلیل
ارشاد باری تعالیٰ ہے: ’’وَ اِذْ اَخَذَ اللہُ مِیْثَاقَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّہٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُوْنَہٗ‘‘ (آل عمران ۱۸۷)
امام علیؒ بن محمد المعروف بفخر الاسلام البزدویؒ (المتوفی ۴۸۲ھ) فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تصریح ہے کہ اہلِ کتاب میں سے ہر آدمی حکمِ خداوندی کے بیان کرنے کا مکلف تھا اور کتمانِ علم اس پر حرام تھا کیونکہ اس امر کے وہ مکلف نہ تھے کہ سب کے سب اجتماعی شکل میں شرقاً و غرباً بیان کرنے کے لیے نکلتے۔ تو اس سے بھی خبرِ واحد کی حجیت ثابت اور واضح ہو گئی (محصلہ مقدمۂ فتح الملہم ص ۸)
رہا یہ شبہ کہ یہ حکم تو پہلی امتوں کے بارے میں ہے جو کہ اہلِ کتاب تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتب اصولِ فقہ میں تصریح موجود ہے مثلاً نور الانوار ص ۲۱۶ میں ہے ’’وشرائع من قبلنا تلزمنا اذا قص اللہ ورسولہ من غیر نکیر الخ‘‘ تو وہ سب احکام ہمارے حق میں بھی حجت ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے بلانکیر بیان فرمائے ہیں۔
بعض احادیث
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ (المتوفی ۱۳۶۹ھ بعمر ۶۴ سال ایک ماہ بارہ دن) فرماتے ہیں کہ خبرِ واحد پر (بشرطیکہ اس کے راوی عادل ہوں) عمل کرنا عملیات میں واجب ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ حضرات صحابہ کرامؓ سے خبرِ واحد پر عمل کرنا ثابت ہے اور بے شمار واقعات سے اس کا ثبوت ہے۔ مجموعی طور پر یہ واقعات حضراتِ صحابہ کرامؓ کے اجماعِ قولی کا فائدہ دیتے ہیں یا کم از کم اخبارِ آحاد پر ایجابِ عمل کے بارے میں اجماعِ قولی کی مثل ضرور ہیں۔ ان واقعات میں سے چند مشہور یہ ہیں:
(۱) حضرت ابوبکر صدیقؓ (م ۱۳ھ) کا وراثتِ جدہ کے مسئلہ میں حضرت مغیرہؓ بن شعبۃ (م ۵۰ھ) اور محمدؓ بن مسلمۃ (م ۴۳ھ) کی خبر پر عمل کرنا جیسے کہ ابوداؤد ص ۴۵ ج ۲ اور ابن ماجہ ص ۱۰۰ میں ہے۔
(۲) حضرت عمرؓ (م ۲۳ھ) کا مجوس سے جزیہ لینے کے بارے میں حضرت عبد الرحمٰنؓ بن عوف (م ۳۳ھ) کی خبر پر عمل کرنا (جیسا کہ ابوداؤد ص ۷۵ میں ہے)۔ اور طاعون کی خبر کے بارے میں بھی انہی کی خبر پر عمل کرنا (جیسا کہ بخاری ص ۸۵۳ ج ۲ میں ہے)۔
(۳) حضرت عمرؓ کا ’’ایجاب غرہ فی الجنین‘‘ کے بارے میں حضرت حملؓ بن مالک ابن النابعۃ کی خبر پر عمل کرنا (ابوداؤد ص ۲۷۲ ج ۲)۔
(۴) نیز حضرت عمرؓ کا خاوند کی دیت سے عورت کی وراثت کے مسئلہ میں ضحاکؓ بن سفیان کی خبر پر عمل کرنا (جیسا کہ ابوداؤد ص ۵۰ ج ۲ و مؤطا مالک ص ۳۴۰ میں ہے)۔
(۵) حضرت عمرؓ کا انگلیوں کی دیت کے بارے میں حضرت عمروؓ بن حزم (م ۵۳ھ) کی خبر پر عمل کرنا (جیسا کہ نسائی ص ۲۱۸ ج ۲) میں حضرت عمروؓ بن حزم کی طویل حدیث میں ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی میں دس دس اونٹ ہیں۔ اس حدیث کی تخریج علامہ ابوالبرکات بن تیمیہؒ نے بھی منتقٰی الاخبار المنسلک مع نیل الاوطار ص ۶۱ ج ۷ میں کی ہے۔ قاضی شوکانیؒ نیل الاوطار ص ۶۴ ج ۷ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ جھنگلیا میں چھ اونٹ، اس کے ساتھ والی میں نو اونٹ، درمیانی میں دس اونٹ، سبابہ یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی میں بارہ اونٹ، اور انگوٹھے میں تیرہ اونٹ دیت دلانے کے قائل تھے۔ پھر حضرت عمرؓ سے اس بات میں رجوع بھی ثابت ہے۔
(۶) حضرت عمرؓ اپنے ہمسائے حضرت عتبانؓ بن مالک کی اخبار کا قبول کرنا (جیسے کہ بخاری ص ۱۹ اور ص ۳۳۴ ج ۱ کی طول حدیث ایلاء میں ذکر ہے کہ میں اور میرا ہمسایہ باری باری حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور وحی وغیرہ کی خبر لا کر مجھے بتاتے اور ایک دن میں حاضری دیتا اور آکر اس کو نئی خبر وغیرہ بتاتا)۔
(۷) حضرت ابنِ عمرؓ کا (م ۷۳ھ) مسح علی الخفین کے بارے میں حضرت سعدؓ بن ابی وقاص (م ۵۵ھ) اور حضرت عمرؓ کی خبر پر عمل کرنا (جیسے کہ مؤطا مالک ص ۱۲ میں ہے)۔
(۸) حضرت عثمانؓ کا متوفی عنھا زوجھا کی عدت کے دوران ’’قیام فی بیتھا‘‘ کے بارے میں حضرت فریعۃؓ بنت مالک بن منان کی خبر پر عمل کرنا (جیسے کہ ابوداؤد ص ۳۱۵ میں ہے)۔ اور اسی طرح تواتر سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اکیلے آدمی کو بھی تبلیغِ احکام کے لیے بھیجا کرتے تھے مثلاً حضرت معاذؓ بن جبل کا یمن بھیجنا جیسے کہ بخاری ص ۱۸۷ ج ۱ میں ہے۔
غرضیکہ اس کثرت سے اخبارِ آحاد پر عمل ذخیرۂ احادیث سے ثابت ہے کہ شمار میں نہیں آ سکتا۔ پھر اگر اخبارِ آحاد کا قبول کرنا واجب نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کا اکیلے اکیلے کو تبلیغِ احکام کے لیے بھیجنے کا کیا فائدہ تھا؟ (مقدمہ فتح الملہم ص ۷)
مزید چند حوالے
منجملہ ان احادیث سے حضرت براءؓ کی روایت بھی ہے جس کے آخر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی (حضرت عبادؓ بن نہیک) کسی مسجد کے قریب سے گزرے اور اہلِ مسجد رکوع میں تھے۔ حضرت عبادؓ کہنے لگے، بخدا میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نماز مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھ کر آیا ہوں۔ اہلِ مسجد اسی حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے، جیسے کہ بخاری ص ۱۱ ج ۱ میں ہے۔
منجملہ ان احادیث سے حضرت براء اور عبد اللہؓ بن ابی اوفٰی کی روایت ہے جس میں ہے کہ ایک منادی (ابو طلحہؓ) نے آواز دی کہ ہنڈیوں میں جو کچھ پک رہا ہے انڈیل دو جیسے کہ بخاری ص ۶۰۷ ج ۲ میں ہے۔
ان احادیث میں حضرت انس ؓ بن مالک کی روایت بھی ہے کہ میں ابو طلحۃ (زیدٌ بن سہل م ۳۱ھ)، ابوعبیدہؓ (عامرؓ بن عبد اللہ م ۱۸ھ) اور ابیؓ بن کعب (م ۱۹ھ) کو فضیح شراب، جو کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی گئی تھی، پلا رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والے نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے، تو حضرت ابو طلحہؓ فرمانے لگے کہ انسؓ اٹھ کر یہ شراب انڈیل دو، پس میں نے انڈیل دی (بخاری ص ۸۳۶ ج ۲)۔
امام دارقطنیؒ نے بھی دارقطنی ص ۴۹۰ ج ۲ میں اپنی مسند کے ساتھ حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوطلحہؓ کے پاس ابیؓ بن کعب (م ۱۹ھ) اور سہل بن بیضاء تمر اور بسر کی، یا فرمایا کہ تمر اور رطب کی شراب پیتے تھے اور میں پلا رہا تھا۔ وہ اتنی تیز تھی کہ قریب تھا کہ ان کو مدہوش کر دیتی۔ پس ایک مسلمان آدمی گزرا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسؓ جو کچھ برتن میں ہے انڈیل دو۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو ذرا تحقیق کر لیں، بلکہ بلا تحقیق ہی صرف ایک آدمی کے کہنے پر انہوں نے کہا اور میں نے وہ انڈیل دی۔ محدث ابو عبد اللہؓ (جن کی نسبت یوں ہے عبید اللہؒ بن عبد الصمدؓ بن المتہدی باللہؒ) فرماتے ہیں کہ بخدا یہ روایت خبرِ واحد کے موجب عمل ہونے پر دال ہے اور مقدمہ فتح الملہم ص ۸ میں ہے۔
امام فخر الاسلامؒ نے فرمایا کہ خبرِ واحد کے حجت ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ خبر راوی کے صدق کی موجودگی میں حجت ہو گی۔ اور خبر چونکہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے لہٰذا راوی میں اخبار کی اہلیت کے بعد عدالت صدق کو ترجیح دے گی۔ اور فسق کذب کا مرجح ہو گا تو رجحانِ صدق کی بنا پر عمل واجب کہنا پڑے گا تاکہ خبرِ واحد عمل کے لیے حجت ہو۔ البتہ چونکہ غیر معصوم میں ایک گونہ سہو اور کذب کا احتمال موجود ہے اس لیے علم الیقین کا فائدہ نہ دے گی۔ اور عمل تو بغیر علم الیقین کے بھی صحیح ہے جیسے کہ قیاس پر غالب رائے کے ساتھ عمل کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح گواہوں کی گواہی پر ظنِ غالب کے ساتھ حکام کا فیصلہ کرنا صحیح ہے۔ لہٰذا عادل کی خبر بھی علمِ ظنی کا فائدہ دے گی اور عمل کے لیے اسی قدر علم کافی ہے۔ البتہ چونکہ علم کی اس قسم میں کچھ اضطراب بھی ہے لہٰذا یہ علم طمانیت سے کم درجہ رکھے گا۔ رہا خبرِ واحد سے علم الیقین کے حصول کا دعوٰی کرنا تو بالکل باطل ہے کیونکہ مشاہدہ صراحتاً اس کا رد کرتا ہے۔ باقی رہی خبر متواتر تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ خبرِ واحد پر اگر امت کا عمل اور تلقّی بالقبول ہو تو پھر معاملہ جدا ہے۔ علامہ القاضی صدر الدین ابن ابی العزا الحنفیؒ فرماتے ہیں:
وخبر الواحد اذا تلقتہ الامۃ بالقبول عملاً بہ و تصدیقاً لہ یفید العلم (الیقینی) عند جماھیر الامۃ وھو احد قسمی المتواتر الخ (شرح عقیدۃ الطحاویۃ ص ۳۹۹ المکتبہ السلفیہ لاہور)
ترجمہ: ’’خبر واحد کو جب امت نے عملی طور پر قبول کیا ہو اور اس کی تصدیق کی ہو تو جمہور امت کے نزدیک وہ علمِ یقین کا فائدہ دیتی ہے اور یہ بھی متواتر کی ایک قسم (بن جاتی) ہے۔‘‘
تعوذ اور قرآن مجید
مولانا سراج نعمانی
تعوذ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ اپنے دروسِ قرآن میں فرماتے ہیں:
’’تعوذ کا معنی ہے خدا کی پناہ حاصل کرنا، تاکہ انسان شیطان کی شر سے بچ سکے کیونکہ انسان تو عاجز اور محتاج ہے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے خدا کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے۔‘‘
تلاوتِ قرآنِ مجید سے پہلے تعوذ پڑھنا مسنون ہے تاکہ انسان کی زبان ان ناپاکیوں سے پاک ہو جائے جو لسانی اور قولی طور پر اس سے سرزد ہوئی ہوں۔ اسی لیے قرآنِ مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآنِ مجید پڑھنے لگو تو اس سے پہلے تعوذ ضرور پڑھا کرو۔ ارشاد ربانی ہے:
فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ۔ (النحل ۹۸)
’’پھر جب تو پڑھے قرآن تو پناہ مانگ اللہ کی شیطان مردود سے۔‘‘
کیونکہ شیطان ہر نیک کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے نہ صرف ہمیں اس کا حکم دیا گیا بلکہ ہم سے پہلے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اللہ کی پناہ میں آنے کی دعائیں مانگیں اور استعاذہ کیا۔ مثلاً نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی اور اللہ پاک نے اس دعا کو نامنظور کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمانے لگے:
قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَسْئَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ (ہود ۴۷)
’’کہا اے میرے پروردگار! بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری، یہ کہ سوال کروں تجھ سے وہ، جس کا علم مجھے نہیں۔‘‘
یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلانا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ حاصل کرتے ہوئے فرمایا تھا:
مَعَاذَ اللہِ اِنَّہٗ رَبِّیْ اَحْسَنَ مَثْوَایَ (یوسف ۲۳)
اور انہی یوسف علیہ السلام کو بنیامین کی جگہ دوسرے بھائی کو پیالے کی چوری کے سلسلے میں بھائیوں نے کچھ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا:
مَعَاذَ اللہِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَہٗ (یوسف ۷۹)
’’پناہ ہے اللہ کی کہ لے لیں ہم سوائے اس شخص کے کہ پائی ہے ہم نے چیز اپنی اس کے پاس۔‘‘
موسٰی علیہ السلام سے بھی تعوذ کے کلمات قرآنِ مجید میں بیان کیے گئے ہیں جب بنی اسرائیل نے گائے کی قربانی کے حکم پر ٹال مٹول کی تو حضرت موسٰی علیہ السلام نے ان کے اقوال و افعال پر فرمایا:
اَعُوْذُ بِاللہِ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْجَاھِلِیْنَ (البقرہ ۶۷)
پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ ہو جاؤں میں نادانوں سے‘‘۔
پھر جب فرعون کے دربار میں دعوتِ حق فرما رہے تھے تو اس وقت یہ فرمایا:
وَقَالَ مُوْسٰی اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مِّنْ کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لَّا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ (المؤمن ۲۷)
’’اور کہا موسٰیٗ نے بے شک میں نے پناہ پکڑی اپنے پروردگار کی تمہارے ہر متکبر سے جو ایمان نہیں لاتا یومِ حساب پر۔‘‘
وَاِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ (الدخان ۲۰)
’’اور بے شک میں نے پناہ پکڑی اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔‘‘
حضرت مریم علیہا السلام کے پاس جب جبرئیل امین مردانہ شکل میں ظاہر ہوئے تو:
قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتُ تَقِیًّا (مریم ۱۸)
’’کہنے لگی تحقیق میں پناہ پکڑتی ہوں رحمٰن کی تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔‘‘
اور انہی مریم علیہا السلام کی پیدائش کے وقت زوجۂ عمران نے کہا تھا:
وَاِنِّیْ اُعِیْذُھَا بِکَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ (مریم ۳۶)
’’اور بے شک میں نے پناہ دی تیری اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔‘‘
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر استعاذہ کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ایک جگہ فرمایا:
وَقُل رَّبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِیْنِ o وَاَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَن یَّحْضُرُوْنَ (المؤمنون ۹۷ و ۹۸)
’’اور کہہ دیجیئے اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ (شیطان) حاضر ہوں میرے پاس۔‘‘
دوسری جگہ کفار اور منکرین کے برتاؤ کے جواب میں یہ تعلیم دی:
اِنْ فِیْ صُدُوْرِھِمْ اِلَّا کِبْرٌ مَّا ھُمْ بِبَالِغِیْہِ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ (مومن ۵۶)
’’نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر (لیکن) وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے پس آپ اللہ کی پناہ مانگیئے۔‘‘
اسی طرح شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ تعلیم دی:
وَاِمَّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ (الاعراف ۲۰۰)
’’اور اگر آپ کو کسی وقت شیطانی وسوسہ ابھارے اور آمادہ کرے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کر لیا کیجئے۔‘‘
اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطانی علوم کے ذریعے سحر کیا گیا تو فرمایا:
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (الفلق ۱)
’’کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔‘‘
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (الناس ۱)
’’کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی۔‘‘
معلوم ہوا کہ قرآن مجید آزادی و سرفرازی کا پیغام لایا۔ انسانوں کو غیر خدا کی محکومیت اور غلامی سے نکال کر ایک خدا کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین کی ؎
یہ ایک سجدہ جسے توں گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
لیکن ہم نے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی بجائے زندہ، مردہ، یا بے جان وڈیروں کی پناہ حاصل کرنے میں فخر سمجھا اور ان کفار کے راستے پر چل نکلے جن کا ذکر قرآن مجید نے اس طرح فرمایا ہے:
وَاَنَّہٗ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْھُمْ رَھَقًا (الجن ۶)
’’اور یہ کہ کئی مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے جنات کی، تو زیادہ ہوا ان کا تکبر۔‘‘
کیا اب بھی خداوند کریم کے دروازے سے ہٹ کر کوئی چوکھٹ ایسی ہے جو اتنی ضمانت اور پناہ دے سکے۔ جب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ہماری نگاہیں مشرق و مغرب کی طرف کیوں متوجہ ہو کر پتھرا رہی ہیں؟ یا ہمیں پناہ دینے والا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نظر آگیا ہے؟
؏ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے
’’شریعت بل‘‘ پر مختلف حلقوں کے اعتراضات
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
- سینٹ میں ’’نفاذ شریعت ایکٹ‘‘ کی منظوری
- پارلیمنٹ اور دستور
- عدالتیں اور قانون سازی
- شریعت بل اور فرقہ واریت
- ملائیت کی اجارہ داری
- خواتین کے حقوق
- اقلیتوں کی شکایت
- حکومت کا طرز عمل اور متوقع پالیسی
- شریعت بل اور تحریک نفاذ شریعت
سینٹ میں ’’نفاذِ شریعت ایکٹ‘‘ کی منظوری
پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ آف پاکستان نے ۱۳ مئی ۱۹۹۰ء کو ’’نفاذِ شریعت ایکٹ ۱۹۹۰ء‘‘ کے عنوان سے ایک نئے مسودہ قانون کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ یہ مسودہ قانون اسی ’’شریعت بل‘‘ کی ترمیم شدہ شکل ہے جو سینٹ کے دو معزز ارکان مولانا سمیع الحق اور مولانا قاضی عبد اللطیف نے ۱۹۸۵ء کے دوران سینٹ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس پر ایوان کے اندر اور باہر مسلسل پانچ برس تک بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری رہا۔ سینٹ آف پاکستان نے شریعت بل کے مسودہ پر نظر ثانی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف کمیٹیاں تشکیل دیں اور سینٹ سیکرٹریٹ کی طرف سے اسے رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے مشتہر بھی کیا گیا جس کے جواب میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے شریعت بل کی حمایت کرتے ہوئے اس کی منظوری پر زور دیا۔ جبکہ صدر پاکستان کی طرف سے شریعت بل کا مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا گیا اور کونسل نے اس پر ایک مفصل رپورٹ پیش کی۔ ایوان سے باہر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے ’’متحدہ شریعت محاذ‘‘ کے نام سے مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دے کر شریعت بل کی منظوری کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر ان تمام مراحل سے گزر کر شریعت بل متعدد ترامیم کے ساتھ ’’نفاذ شریعت ایکٹ ۱۹۹۰ء‘‘ کے نام سے سینٹ آف پاکستان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔
دستوری طریق کار کے مطابق نفاذ شریعت ایکٹ کا یہ مسودہ اب پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں زیر بحث آئے گا جسے سینٹ سے اس کی منظوری کے ۹۰ دن کے اندر اسے منظور یا مسترد کرنا ہے۔ اگر خدانخواستہ قومی اسمبلی نے اسے منظور نہیں کیا تو ارکان سینٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پر دوبارہ غور کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا مطالبہ کریں۔ اس طرح قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان مشترکہ اجلاس میں نفاذ شریعت ایکٹ کو منظور یا معاذ اللہ مسترد کرنے کا حتمی فیصلہ کر سکیں گے۔
۱۹۸۵ء میں جب شریعت بل کو سینٹ سیکرٹریٹ کی طرف سے رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے مشتہر کیا گیا تو اس کی حمایت اور مخالفت میں قومی حلقوں میں بحث و تمحیص کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ بل کے حق اور اس کے خلاف بہت کچھ کہا گیا۔ جن طبقات نے شریعت بل کی اس وقت مخالفت کی ان میں سیاسی حلقے بھی تھے اور مذہبی عناصر بھی مگر مخالفت کی بیشتر وجوہ سیاسی تھیں۔ اور عام طور پر اسے اس پس منظر میں دیکھا جا رہا تھا کہ شاید اس کے پس پردہ حکومت وقت کے سیاسی مقاصد اور عزائم کارفرما ہیں۔ لیکن حکومت کی تبدیلی اور حالات کے پلٹا کھانے کے بعد شکوک و شبہات کے بادل رفتہ رفتہ چھٹنے لگے اور بالآخر مطلع اس حد تک صاف ہوگیا کہ سینٹ میں شریعت بل کی متفقہ منظوری کے بعد اس کے بارے میں قومی اخبارات میں دوبارہ بحث کا آغاز ہوا تو مخالفت میں وہ شدت نظر نہیں آرہی جو کچھ عرصہ قبل شریعت بل کا نام سامنے آتے ہی قومی اخبارات کی نمایاں سرخیوں کی زینت بن جایا کرتی تھی۔ بالخصوص شریعت بل کی مخالفت کرنے والے معروف مذہبی حلقوں مثلاً جمعیۃ علماء پاکستان، جمعیۃ اہل حدیث اور جمعیۃ علماء اسلام (فضل الرحمان گروپ) کی طرف سے اس کی حمایت کا اظہار حالات میں بہتر اور خوش آئند تبدیلی کا غماز ہے۔ اور اس امر کے آثار واضح ہو رہے ہیں کہ قومی اسمبلی سے شریعت بل کو منظور کرانے کے لیے ملک کے تقریباً سبھی مذہبی حلقے مشترکہ حکمت عملی اور جدوجہد کا راستہ اختیار کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔ مگر اس کے باوجود قومی اخبارات میں نفاذ شریعت ایکٹ کے بارے میں ہونے والی بحث میں مخالفت کا پہلو ابھی تک نمایاں ہے اور اس کے خلاف بعض ایسے خدشات و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے جن کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا ضروری ہے۔
ہمارے نزدیک نفاذ شریعت ایکٹ کے بارے میں قومی اخبارات میں ہونے والی بحث میں مخالفت کا پہلو نمایاں ہونے کی کچھ وجوہ ہیں جنہیں بہرحال پیش نظر رکھنا ہوگا۔
- سینٹ نے ترامیم کے ساتھ شریعت بل کا جو مسودہ منظور کیا ہے اسے قومی اخبارات نے تا دمِ تحریر شائع نہیں کیا۔ صرف ایک قومی اخبار نے اس کا مسودہ شائع کیا ہے لیکن وہ نہ صرف یہ کہ نامکمل ہے بلکہ اس میں وہ ترامیم بھی شامل نہیں ہیں جو سینٹ نے منظوری کے مرحلے میں آخری وقت اس میں سموئی ہیں۔ اس لیے ملک کی بیشتر آبادی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ منظور شدہ مسودہ کیا ہے۔
- بیشتر قومی اخبارات اپنی طبقاتی وابستگیوں اور کچھ مخصوص ملکی و بین الاقوامی عوامل کے ہاتھوں اپنی پالیسی کو عملاً سیکولر رکھنے پر مجبور ہیں جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ شریعت بل یا شریعت سے متعلقہ کسی بھی امر کی مخالفت میں آنے والے بیانات و مضامین ان اخبارات میں نمایاں اور فل ایڈیشن جگہ پاتے ہیں جبکہ حمایت میں آنے والے بیانات و مضامین کو کسی ایک ایڈیشن میں غیر نمایاں جگہ ملتی ہے۔ اس طرح عوام کو دونوں طرف کا موقف اور دلائل برابر سطح پر معلوم کرنے کا موقع نہیں ملتا اور شرعی امور کے بارے میں عوام میں شکوک و شبہات اور تذبذب کی فضا قائم رکھنے کی پالیسی میں قومی اخبارات یا ان کو کنٹرول کرنے والی لابیاں کسی حد تک کامیاب رہتی ہیں۔
- شریعت بل کی حمایت کرنے والی لابیوں میں باہمی ربط و نظم کا فقدان ہے اور وہ اپنے موقف کو سائنٹیفک انداز میں رائے عامہ تک صحیح طور پر پہنچانے میں کامیاب نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا موقف معقول اور منطقی ہونے کے باوجود دانشور اور تعلیم یافتہ طبقوں کے ذہنوں کے دروازوں پر دستک نہیں دے پاتا اور شکوک و خدشات کا ماحول بدستور قائم رہتا ہے۔
اس پس منظر میں ان شبہات پر ایک نظر ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو قومی اخبارات میں شائع ہونے والے بعض بیانات میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ
- پارلیمنٹ اور دستور پر شریعت بل کو بالادستی دے دی گئی ہے جس سے آئین کی بالاتر حیثیت اور پارلیمنٹ کی خودمختاری مجروح ہوگی۔
- قانون سازی کے اختیارات عدالتوں کو دے دیے گئے ہیں۔
- شریعت بل کے ذریعے فرقہ واریت کے فروغ کی راہ ہموار ہوگی۔
- شریعت بل کے نفاذ سے ملا ازم کا غلبہ ہو جائے گا اور ملائیت کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی۔
- شریعت بل کے ذریعے عورتوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور ان کی حیثیت کم کر دی گئی ہے۔
پارلیمنٹ اور دستور
جہاں تک پارلیمنٹ اور دستور پر شریعت بل کی بالادستی کا تعلق ہے یہاں ایک ہلکا سا مغالطہ اور ہیرپھیر ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ یہ بالادستی جس کو ہوّا بنایا جا رہا ہے ’’شریعت بل‘‘ کی نہیں بلکہ ’’شریعت‘‘ کی ہے کیونکہ شریعت بل تو خود اسی پارلیمنٹ کی منظوری کا محتاج ہے اور آئینی حدود کے اندر منظوری کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ جب دستور اور پارلیمنٹ خود اس بل کو تخلیق کر رہے ہیں تو آخر بل کی ان دونوں پر بالادستی کیسے ہو سکتی ہے؟ بات بل کی نہیں بلکہ شریعت کی ہے جسے بل کی اوٹ میں متنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رہی بات شریعت کی تو اس میں کسی مسلمان کے لیے کلام کی گنجائش نہیں ہے کہ شریعت کو پارلیمنٹ اور دستور پر بہرحال بالادستی حاصل ہے۔
پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے جس کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور جس کی دستوری پالیسیوں کا سرچشمہ ’’قراردادِ مقاصد‘‘ ہے جو واضح طور پر خدا کی حاکمیت مطلقہ کی ضمانت دیتی ہے۔ اسی لیے ان دو دستوری بنیادوں کی موجودگی میں یہ تصور کہ دستور کی کسی دفعہ اور قرآن و سنت کے کسی حکم میں تعارض کے وقت پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہوگی، نہ صرف مسلمان کے عقیدہ و ایمان کے منافی ہے بلکہ خود دستور کی نظریاتی بنیادوں سے متصادم ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ کی خودمختاری کا یہ تصور کہ وہ شریعت کی حدود اور قرآن و سنت کے احکامات کے دائرہ سے بالاتر ہو کر قانون سازی کا حق رکھتی ہے، یورپی جمہوریتوں میں تو یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے بارے میں اس آزادی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس نظریاتی اسلامی ملک میں دستور اور پارلیمنٹ کو شریعت کے دائرہ کا پابند رہنا ہی پڑے گا ورنہ اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔
پھر دستور اور پارلیمنٹ پر شریعت کو یہ بالادستی شریعت بل نے عطا نہیں کی بلکہ یہ بالادستی قراردادِ مقاصد کے ذریعے حاصل ہوئی جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں پاس ہوئی تھی اور جسے جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے موجودہ دستور کا باقاعدہ اور واجب العمل حصہ قرار دیا تھا۔ پارلیمنٹ اور دستور پر شریعت کو بالادستی دینے والی قراردادِ مقاصد کو منظور دستور ساز اسمبلی نے کیا تھا اور اسے دستور کا باقاعدہ حصہ سپریم کورٹ کے بخشے ہوئے اختیارات کے تحت جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے قرار دیا تھا۔ جبکہ شریعت بل اور نفاذ شریعت ایکٹ نے تو صرف اپنے جواز کے لیے اس کا حوالہ دیا ہے۔ چنانچہ نفاذ شریعت ایکٹ کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ
’’ہر گاہ کہ قراردادِ مقاصد کو، جو کہ پاکستان میں شریعت کو بالادستی عطا کرتی ہے، دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان ۱۹۷۳ء کے مستقل حصے کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے اور ہرگاہ کہ مذکورہ قراردادِ مقاصد کے اغراض کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے فی الفور نفاذ کو یقینی بنایا جائے، لہٰذا حسب ذیل قانون بنایا جاتا ہے۔‘‘
اس لیے اگر دستور اور پارلیمنٹ پر شریعت کی بالادستی (معاذ اللہ) قابل اعتراض ہے تو اس کی ذمہ داری اس شریعت بل پر عائد نہیں ہوتی بلکہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ اور ۱۹۷۳ء کے دستور کو جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کی ترامیم سمیت قبول کرنے والے تمام عناصر اس بالادستی کو تسلیم کرنے اور اس کا احترام کرنے کے بہرحال پابند ہیں۔
عدالتیں اور قانون سازی
یہ بات بھی محض ایک مغالطہ کے سوا کچھ نہیں کہ شریعت بل میں عدالتوں کو قانون سازی کے اختیارات دے دیے گئے ہیں، کیونکہ شریعت بل میں عدالتوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
- عدالتیں شریعت کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں۔
- شریعت پاکستان کا اعلیٰ ترین قانون ہوگی۔
- شریعت کی تشریح و تفسیر کرتے وقت قرآن و سنت کی تشریح و تفسیر کے مسلمہ اصول و قواعد کی پابندی کی جائے گی۔
اب اس میں دیکھیں کہ عدالتوں کو قانون سازی کا حق کہاں سے مل گیا ہے؟ بلکہ وہ تو پابند ہیں کہ مقدمات کا فیصلہ شریعت کے مطابق کریں جبکہ شریعت کے قوانین قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی صورت میں پہلے سے موجود ہیں۔ اب اگر کوئی عدالت کسی زیرسماعت مقدمہ کا فیصلہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کرتی ہے تو اس نے قانون وضع تو نہیں کیا کہ قانون پہلے سے موجود ہے، عدالت نے صرف اس کا اطلاق کیا ہے اور اس کی تعبیر و تشریح کی ہے۔ کوئی نیا قانون وضع کرنے اور کسی پہلے سے موجود قانون کی تعبیر و تشریح کر کے ایک وقوعہ پر اس کا اطلاق کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق ایسا نہیں جسے اعتراض کرنے والے حضرات سمجھتے نہ ہوں لیکن اس کے باوجود مسلسل مغالطہ دیا جا رہا ہے۔ شریعت بل نے کوئی قیامت نہیں ڈھائی بلکہ عدالتوں کو قوانین کی تعبیر و تشریح کے وہی اختیارات دیے ہیں جو دنیا کے ہر دستور اور ہر قانونی نظام میں عدالتوں کو حاصل ہیں اس لیے اس پر واویلا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
شریعت بل اور فرقہ واریت
شریعت بل کے ذریعہ فرقہ واریت کے فروغ کا بھی واویلا کیا جا رہا ہے حالانکہ عملاً شریعت بل کے سینٹ سے منظور ہوجانے کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ مذہبی محاذ پر مولانا فضل الرحمان، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر ساجد میر اور مولانا عبد الستار خان نیازی کی جماعتیں، جو اس سے قبل شریعت بل کی مخالفت میں پیش پیش تھیں، اب اس کی حمایت کر رہی ہیں اور اہل السنتہ والجماعۃ کے تینوں مکاتب فکر دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کا کوئی قابل ذکر حلقہ ایسا نہیں ہے جو شریعت بل کا اب مخالف ہو۔ اس لیے یہ کہنا حقیقت کے برعکس ہے کہ شریعت بل فرقہ وارانہ کشمکش میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ البتہ اہل تشیع کے بعض انتہا پسند حلقوں کی طرف سے مخالفت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن وہ بھی بل کے مندرجات سے پوری طرح واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ شریعت بل کی دفعہ نمبر ۲ شق (ب) میں شریعت کی تشریح و تعبیر کے طریق کار کے ضمن میں دستور کی دفعہ ۲۲۷ شق (۱) کا واضح طور پر حوالہ دیا گیا ہے جس میں پرسنل لاء میں اہل تشیع کے لیے ان کے فقہی مسلک کے مطابق قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا حق تسلیم کیا گیا ہے، اور اسے شریعت بل میں بھی جوں کا توں برقرار رکھا گیا ہے اس لیے یہ واویلا بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے۔
ملائیت کی اجارہ داری
بعض حلقے اس پروپیگنڈا میں مصروف ہیں کہ شریعت بل کے نفاذ سے ملا ازم ملک میں غالب ہو جائے گا اور ملائیت کی اجارہ داری قائم ہوگی۔ یہ بات بھی حقیقت کے برعکس ہے کیونکہ شریعت بل میں قرآن و سنت کے قوانین کے نفاذ اور شریعت کی تعبیر و تشریح کے تمام اختیارات اعلیٰ عدالتوں کو سونپ دیے گئے ہیں۔ جبکہ ان عدالتوں میں سے صرف وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت ایپلٹ بنچ میں علماء کی نمائندگی ثانوی حیثیت سے موجود ہے۔ باقی عدالت ہائے عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں علماء کرام سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔
قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے استحقاق پر علماء کرام اگر اڑ جاتے تو یہ بات قابل فہم بھی تھی کیونکہ جن جج صاحبان نے قرآن و سنت کا باضابطہ علم حاصل نہیں کیا انہیں قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح میں تیس تیس سال تک قرآن و حدیث اور فقہ کی تدریسی خدمات سرانجام دینے والے جید علماء پر ترجیح دینا کسی بھی طرح قرینِ قیاس نہیں ہے۔ لیکن یہ علماء کرام کا ایثار اور نفاذِ اسلام کے ساتھ ان کی والہانہ وابستگی کا اظہار ہے کہ وہ اپنے اس جائز حق سے عدالتوں کے حق میں دستبردار ہوگئے ہیں اور انہوں نے شریعت بل کے ذریعے صرف تعبیر و تشریح کے مسلمہ قواعد کی پابندی کی شرط لگا کر یہ حق بھی جج صاحبان کے سپرد کر دیا ہے۔ اور بلاشبہ اس مرحلہ میں علماء کرام نے اس روایتی کہانی والی ماں کا کردار ادا کرنا پسند کیا ہے جس میں ایک معصوم بچے کی دعوے دار دو ماؤں کے درمیان بچے کو دو ٹکڑے کر کے تقسیم کرنے کی بات کی گئی تو بچے کی حقیقی ماں نے معصوم بچے کی زندگی کی خاطر اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر بچہ سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا کہ اس طرح بچہ دو ٹکڑے ہونے سے تو بچ جائے گا۔ بالکل اسی طرح علماء کرام نے اپنا جائز اور منطقی استحقاق چھوڑ کر ایثار و قربانی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ نفاذِ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور اگر اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت بل کے نفاذ سے ملاؤں کی اجارہ داری قائم ہوگی تو اس کی اس بات کو کم عقلی یا عناد کے علاوہ اور کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا۔
خواتین کے حقوق
شریعت بل کے حوالہ سے خواتین میں یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس شریعت بل کے ذریعے عورتوں کے حقوق غصب ہو جائیں گے اور ان کی حیثیت کم ہو جائے گی۔ حالانکہ شریعت بل کے پورے مسودہ میں خواتین کے حوالے سے مثبت یا منفی کوئی ایک دفعہ یا شق موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی اعتراض کرنے والے حلقے شریعت بل کی کسی ایک دفعہ کی نشاندہی کر سکے ہیں جو ان کے بقول خواتین کے حقوق کے منافی ہے۔ ہاں اصولی طور پر تمام ملکی معاملات پر قرآن و سنت کے احکام کی بالادستی کی بات شریعت بل میں ضرور کی گئی ہے اور اس بارے میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خواتین کی عزت و احترام اور حقوق و مفادات کا تحفظ جس قدر شریعت اسلامیہ میں کیا گیا ہے اس کی کسی اور نظام میں مثال نہیں ملتی۔
اس حقیقت کو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے سوائے ان چند مغرب زدہ خواتین کے جن کے ہاں عورتوں کے حقوق کا تصور یہ ہے کہ پاکستان میں مغربی طرز کے معاشرہ کے فروغ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور بے پردگی،جنسی انارکی اور اخلاق باختگی کی تمام مغربی اقدار بلا روک ٹوک پاکستان میں رائج ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ خواتین کی بیشتر تنظیموں نے مغرب زدہ عورتوں کے اس پراپیگنڈا کو مسترد کر کے شریعت بل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ خواتین میں مغربی لابیوں کے زہریلے پراپیگنڈا کے ازالہ کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہیں۔
اقلیتوں کی شکایت
ہم یہ گزارشات مکمل کر چکے تھے کہ شاہدرہ لاہور سے ماہنامہ المذاہب کے مدیر محترم جناب محمد اسلم رانا کی طرف سے، جو مسیحیت کے ماہر اور اقلیتوں کے جائز حقوق کے تحفظ کے علمبردار ہیں، ایک مسیحی ماہنامہ شاداب میں شائع شدہ مضمون کی فوٹو کاپی ہمیں موصول ہوئی جس میں شریعت بل کے خلاف ایک لمبی تمہید کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ
’’اگر اس بل کی منظوری ناگزیر ہی ہو جائے تو کم از کم اقلیتوں خصوصاً مسیحیوں کو دیگر شرعی آرڈیننس سمیت شریعت بل سے مستثنیٰ قرار دیا جائے اور ان کے تمام تر فقہی، مذہبی اور سماجی مسائل ملکی قوانین اور ان کے پرسنل لاز کے مطابق حل کیے جائیں اور شریعت بل کو وطن عزیز کے آئین پر کوئی فوقیت نہ دی جائے۔‘‘
اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ جہاں تک پرسنل لاء کا تعلق ہے، شریعت بل کی دفعہ ۱ شق ۴ میں اس امر کی واضح طور پر صراحت کر دی گئی ہے کہ
’’اس (بل) میں شامل کسی امر کا اطلاق غیر مسلموں کے شخصی قوانین پر نہیں ہوگا۔‘‘
اس لیے اس ضمن میں کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ تمام شرعی قوانین سے غیر مسلموں کو مستثنیٰ قرار دینے کا مطالبہ دوسرے لفظوں میں ہر غیر مسلم اقلیت کے لیے مستقل اور متوازی پبلک لاء کے نفاذ کا مطالبہ ہے جسے نہ تو قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عقل و انصاف کے کسی اصول پر پورا اترتا ہے۔ باقی رہی آئین پر شریعت کی بالادستی کی بات تو یہ غیر مسلموں کے سوچنے کی بات نہیں اور نہ ہی انہیں یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے گمراہ کن مشورے دے کر مسلمانوں کے مذہبی امو رمیں مداخلت کریں اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔
حکومت کا طرز عمل اور متوقع پالیسی
شریعت بل کی مخالفت میں اٹھنے والی آوازوں کا ایک نظر جائزہ لینے کے بعد یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں حکومتی حلقوں کے طرز عمل پر بھی نگاہ ڈال لی جائے تاکہ ملک کے دینی حلقے اس کی روشنی میں اپنی جدوجہد کا دائرہ اور رخ متعین کر سکیں۔
جب تک شریعت بل کا مسودہ سینٹ کی مختلف کمیٹیوں میں زیر بحث رہا حکومت کی دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ دو وفاقی وزراء وزیر قانون اور وزیر مذہبی امور ان کمیٹیوں میں شامل ہونے کے باوجود ان سے لاتعلق رہے، ایک دو اجلاسوں کے سوا وہ کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ شریعت بل نے منظور تو ہونا نہیں اس میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ حتیٰ کہ منظوری کے آخری مرحلہ میں وفاقی وزیر قانون اپنی تجویز کردہ ترامیم کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی ترامیم مسترد ہوگئیں۔ مگر سینٹ میں شریعت بل کی متفقہ منظوری نے حکومتی حلقوں کو اضطراب انگیز حیرت سے دوچار کر دیا اور ایک دو دن کی ’’سکتہ نما‘‘ خاموشی کے بعد وفاقی وزراء نے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا جو شریعت بل کے مخالفین کی طرف سے ایک عرصہ سے الاپا جا رہا ہے۔ اس طرح حکومت کا نقطۂ نظر واضح ہوگیا کہ وہ سینٹ میں شریعت بل کی منظوری پر بے حد مضطرب ہے اور یہ اضطراب اس کی آئندہ پالیسی کے رخ کو واضح کر رہا ہے۔
اس لیے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ حکومت قومی اسمبلی میں شریعت بل کی منظوری کو روکنے کے لیے ہرممکن ذریعہ اختیار کرے گی۔ اس سلسلہ میں حکومت کی متوقع پالیسی پر نظر ڈالنے سے پہلے اس طریق کار کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس سے گزر کر یہ شریعت بل ملک میں باضابطہ قانون کی شکل اختیار کر سکے گا۔
آئینی ماہرین کے مطابق شریعت بل سینٹ سے منظور ہونے کی تاریخ سے ۹۰ دن کے اندر قومی اسمبلی میں پیش ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس مدت کے دوران شریعت بل قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل نہ ہو سکا تو وہ خودبخود ختم ہو جائے گا جیسا کہ اس سے قبل سینٹ سے منظور ہونے والا نواں آئینی ترمیمی بل جو نفاذ شریعت ہی کے بارے میں تھا ۹۰ دن کے اندر قومی اسمبلی میں پیش نہ ہو سکنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس دوران شریعت بل قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں آگیا تو قومی اسمبلی اسی مدت کے دوران اسے منظور یا مسترد کرنے کی پابند ہے، اور وہ منظور یا مسترد کرنے کے علاوہ اس میں ترامیم بھی تجویز کر سکتی ہے۔
قومی اسمبلی میں شریعت بل مسترد ہونے کی صورت میں سینٹ کی طرف سے پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور پھر مشترکہ اجلاس میں بل کو منظور یا مسترد کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ جبکہ ترامیم کی صورت میں بل کا مسودہ دوبارہ سینٹ میں جائے گا اور سینٹ ازسرنو اس پر غور کرے گی۔
اس صورتحال میں شریعت بل سے نمٹنے کے لیے حکومتی حلقوں کی پالیسی کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔
- حکومت کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ شریعت بل قومی اسمبلی میں مقررہ مدت کے اندر پیش نہ ہونے پائے تاکہ یہ بھی نویں آئینی ترمیم بل کی طرح اپنی موت آپ مر جائے۔ اس کی عملی صورت یہ ہوگی کہ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران تو اس میں بجٹ کے سوا اور کسی مسئلہ پر بحث نہیں ہو سکتی۔ بجٹ اجلاس جون کے آخر تک جاری رہے گا، اس کے بعد قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس اس مدت کے گزر جانے کے بعد (جو ۱۱ اگست کو پوری ہو رہی ہے) طلب کیا جائے تاکہ مدت گزر جانے کی وجہ سے اس ایوان میں پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اس حربے کا جواب موجود ہے کہ بجٹ اجلاس ختم ہوجانے کے بعد اپوزیشن ارکان اسمبلی کی طرف سے ریکویزیشن پر مقررہ مدت کے اندر اسمبلی کے اجلاس کا مطالبہ کیا جائے۔ اس صورت میں حکومت شریعت بل کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لانے کی پابند ہوگی۔
- قومی اسمبلی میں بل کے پیش ہوجانے کے بعد حکومت کے پاس اسے ناکام بنانے کا دوسرا حربہ یہ ہوگا کہ اس میں ترامیم پیش کی جائیں تاکہ یہ سینٹ میں واپس جائے اور اس عل میں اتنی سست روی سے کام لیا جائے کہ سینٹ کے نصف ارکان کے دوبارہ انتخاب کا مرحلہ آجائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سینٹ میں آئی جے آئی (اسلامی جمہوری اتحاد) کی غالب اکثریت ہے اور اسی اکثریت کی وجہ سے شریعت بل پاس ہوا ہے۔ جبکہ مارچ ۱۹۹۱ء میں سینٹ کے نصف ارکان کی رکنیت ختم ہو رہی ہے اور ان کی جگہ نئے ارکان منتخب ہوں گے جن میں ظاہر ہے کہ سندھ اور سرحد سے پیپلز پارٹی کی اکثریت ہوگی اور پنجاب و بلوچستان سے بھی پی پی پی کچھ نہ کچھ نشستیں ضرور حاصل کرے گی جس سے سینٹ کی موجودہ شکل برقرار نہیں رہے گی۔ اس طرح سینٹ کے پاس کردہ شریعت بل کو سینٹ میں ہی مسترد کرنے یا ان میں من مانی ترامیم کے ذریعے اس کا حلیہ بگاڑنے کی راہ آسان ہو جائے گی۔ اس لیے وفاقی حکومت کے پاس شریعت بل کو ناکام بنانے کا واحد اور بظاہر کامیاب حربہ یہی ہے کہ ترامیم پیش کر کے اسے اس وقت تک مؤخر کیا جائے جب تک سینٹ میں پیپلز پارٹی کو واضح پوزیشن حاصل نہیں ہو جاتی اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ حسب منشا سلوک کر کے نفاذ شریعت کے ’’خطرہ‘‘ سے نجات حاصل کر لی جائے۔
ہمارا خیال یہ ہے کہ وفاقی حکومت قومی اسمبلی میں واضح اکثریت رکھنے کے باوجود شریعت بل کو مسترد کرنے کا راستہ اختیار نہیں کرے گی کیونکہ اس سے اس کی بدنامی کے علاوہ یہ خطرہ بھی ہوگا کہ سینٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے مطالبہ کی صورت میں اگر متحدہ حزب اختلاف نے شریعت بل کی حمایت کا فیصلہ کر لیا تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں متحدہ حزب اختلاف کی اکثریت کی وجہ سے شریعت بل کے پاس ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس لیے حکومت مسترد کرنے کی بجائے ترامیم کا راستہ اختیار کرے گی اور ترامیم پیش کرنے میں بھی حکومت کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ ترامیم حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے آئیں تاکہ بل کی منظوری میں تاخیر کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی نمایاں ہو کہ شریعت بل اپوزیشن کے حلقوں میں ابھی تک متنازعہ ہے اور حکومت اس تاخیر کو اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال کر خود بدنامی سے بچ سکے۔ اگر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے ترامیم نہ آئیں تو حکومت آخری حربے کے طور پر اپنے فلور سے ترامیم پیش کرائے گی تاکہ مسئلہ کو کھینچ تان کر مارچ ۱۹۹۱ء تک لمبا کیا جا سکے۔
اس پس منظر میں حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے ہم انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کے اس ’’دام ہمرنگ زمین‘‘ سے ہوشیار رہیں۔ بعض ذمہ دار حضرات کی طرف سے یہ عندیہ سامنے آیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں شریعت بل زیر بحث آنے کے بعد اس میں ترامیم پیش کریں گے۔ ان حضرات کے خلوص اور شریعت بل کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے جذبے سے انکار نہیں لیکن ترامیم پیش کرنے کا فائدہ حکومت کو ہوگا اور وہ اس طرح شریعت بل کو حزب اختلاف کے حلقوں میں متنازعہ ظاہر کرنے کے علاوہ مطلوبہ تاخیر حاصل کرنے میں پھر کامیاب ہو جائے گی جس کے بعد بات ترامیم پیش کرنے والے بزرگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور وہ شریعت بل کو قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کرانے کے آخری چانس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
شریعت بل کا یہ مسودہ بحث و تمحیص اور مسلسل ترامیم کے طویل مراحل سے گزر کر سامنے آیا ہے اس کے باوجود اس میں ترامیم کی گنجائش موجود ہے۔ اگر اس مسودہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز ہیں تو ان کی اہمیت سے انکار نہیں مگر انہیں ترامیم کی صورت میں پیش کرنا انتہائی پرخطر راستہ ہے جس پر چلنے کا رسک نفاذ شریعت سے دلچسپی رکھنے والے کسی بھی طبقہ کو نہیں لینا چاہیے۔ قانون میں ترمیم اس کی منظوری کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے نیا مسودہ قانون بھی پیش ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت یہ مسودہ جیسا بھی ہے اسے اسی صورت میں قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے کی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے ورنہ پورا روپیہ وصول کرنے کی ضد میں بارہ آنے کی وصولی کا امکان بھی کھو بیٹھیں گے۔ اور سینٹ سے ایک دفعہ منظور ہوجانے کے بعد شریعت بل کو دوبارہ حکومتی چالوں کی بھینٹ چڑھانے کی بدنامی اور روسیاہی الگ حصے میں آئے گی۔
اس لیے ملک بھر کے دینی و سیاسی حلقوں سے ہماری مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ اس صورتحال کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں اور شریعت بل کو حکومتی چالوں اور تاخیری حربوں سے بچا کر اسے قومی اسمبلی سے منظور کرانے کے لیے منظم جدوجہد کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر دینی حلقے اس مقصد کے لیے عوامی دباؤ منظم کرنے میں کامیاب ہوگئے اور ترامیم کے حوالے سے حزب اختلاف کی کوئی جماعت حکومتی چال کا شکار نہ ہوئی تو شریعت بل کو مقررہ مدت کے اندر قومی اسمبلی سے منظور کرانے کے سوا حکومت کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا اور پاکستان کے قیام کے ۴۲ سال بعد ہم شریعت کو ملک کا سپریم لاء قرار دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔
شریعت بل اور تحریک نفاذ شریعت
ماہِ رواں کی سترہ تاریخ کو فلیش مین ہوٹل راولپنڈی صدر میں منعقدہ آل پارٹیز نفاذِ شریعت کانفرنس میں ’’شریعت بل‘‘ کو قومی اسمبلی سے منظور کرانے اور سودی نظام کی وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے پورے ملک میں تحریک نفاذ شریعت منظم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
’’آل پارٹیز نفاذِ شریعت کانفرنس‘‘ جمعیۃ علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل اور شریعت بل کے محرک سینیٹر مولانا سمیع الحق کی دعوت پر منعقد ہوئی جس سے مولانا عبد الستار خان نیازی، مولانا فضل الرحمان، مولانا محمد اجمل خان، مولانا محمد عبد اللہ، صاحبزادہ حاجی فضل کریم، مولانا معین الدین لکھوی، مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، مولانا ضیاء القاسمی، مولانا قاضی احسان الحق، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، مولانا وصی مظہر ندوی اور دیگر سرکردہ علماء کرام کے علاوہ قومی شخصیات میں سے نوابزادہ نصر اللہ خان، جناب غلام مصطفیٰ جتوئی، میاں محمد نواز شریف، اقبال احمد خان، راجہ محمد ظفر الحق، جناب اعجاز الحق، پروفیسر غفور احمد اور جناب طارق محمود ایم این اے نے بھی خطاب کیا۔
’’شریعت بل‘‘ اس وقت قومی اسمبلی کے حوالے ہو چکا ہے اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور خواجہ طارق رحیم کے ایک بیان کے مطابق اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں زیر بحث آنے والا ہے۔ اس مرحلہ پر ملک کے اہم سیاسی و دینی حلقوں کا یہ اتفاق و اشتراک بلاشبہ ایک نیک فال اور عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی اہل دین نے متحد ہو کر کسی جدوجہد کا آغاز کیا ہے انہیں اہل سیاست کی حمایت بھی حاصل ہوئی ہے اور وہ جدوجہد میں کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئے ہیں۔ اہل دین کا اتحاد ہمارے ملک کے بہت سے مسائل کا حل اور نفاذِ اسلام کی جدوجہد کی کامیابی کی کلید چلا آرہا ہے۔
ہم ’’تحریک نفاذِ شریعت‘‘ کے آغاز کے اس فیصلہ کا خیرمقدم کرتے ہوئے دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت اہل دین کے اتحاد کو ملت کے لیے مبارک کریں اور اسے ملک میں شریعت اسلامیہ کی بالادستی کا ذریعہ بنائیں، آمین یا الہ العالمین۔
عیسائی اور یہودی نظریۂ الہام
محمد اسلم رانا
کہنہ مشق اور پرجوش عیسائی مبلغ پادری برکت اے خان ایک ریٹائرڈ سکول ماسٹر ہیں۔ دورانِ ملازمت سے ہی تبلیغی سرگرمیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کی اکثر و بیشتر تحاریر کے مخاطبین مسلمان ہوتے ہیں۔ چند برس پیشتر انہیں اعزازی طور پر پادری بنا دیا گیا۔ رسمِ تقدیس سیالکوٹ چھاؤنی کے قدیم وسیع اور خوبصورت ہولی ٹرنٹی کیتھیڈرل نامی گرجاگھر میں منعقد ہوئی۔ راقم بھی اس تقریب میں شامل تھا۔
مؤقر جریدہ ’’الشریعۃ‘‘ بابت اپریل ۱۹۹۰ء (صفحہ ۴۰ کالم اول) میں حافظ محمد عمار خان ناصر نے پادری مذکور کی کتاب ’’اصولِ تنزیل الکتاب‘‘ (صفحات ۵، ۶) کے مندرجہ ذیل الفاظ نقل کیے ہیں:
’’آسمان پر الہامی کتابوں کی موجودگی اور ان کی آیات کے لفظ بلفظ کسی خاص زمان میں نزول کا جو عقیدہ اہلِ اسلام کے درمیان مروّج ہے، کتابِ مقدس کے صحائف کے متعلق نہ یہودیوں میں اور نہ مسیحیوں میں ایسا عقیدہ کبھی مروّج ہوا ہے۔‘‘
عیسائیوں کی کتاب مقدس، بائبل، رومن کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک ۷۲ اور (پادری صاحب کے) پروٹسٹنٹ فرقہ کے ہاں ۶۶ کتابوں پر مشتمل ہے۔ متنازعہ فیہ کتابوں کو اپوکریفہ کہتے ہیں۔ بائبل کی اکثر و بیشتر کتابوں کے مصنفین سن و مقام تحریر اور مخاطبین کا تحقیق کچھ پتہ نہیں۔ بس کتابوں کے مندرجات اور تاریخ کی مدد سے اندھیرے میں کچھ تیر چلائے جاتے ہیں۔
عیسائی نظریۂ الہام
سیدھے سادے چند الفاظ میں عیسائی نظریۂ الہام یہ ہے کہ عیسائی علماء کی کمیٹی جس کتاب کو قبول کر لے وہ الہامی، مقدس، مستند، خدا کا کلام اور مدارِ نجات ہے۔ بائبل کی مخصوص مسیحی کتابیں اسی طرح مسیحی علماء کی مختلف کونسلوں، کمیٹیوں اور مجلسوں نے پاس کی تھیں۔ اور یہ انتخاب بھی کوئی حتمی شے اور یقینی امر نہیں ہے۔ افریقن مشنری نہلز ایسی مجالس کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:
’’ہم بھی ان سے اتفاق یا اختلاف کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔‘‘ (Christians Answer Muslims - By Gerhard Nehls - 1980, p 118)
یعنی فی زمانہ بھی مسیحی علماء کی کوئی کونسل بائبل کی کسی کتاب کو غیر مستند قرار دینے اور اس مجموعہ سے نکال باہر کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ چند آراء پیشِ خدمت ہیں:
’’اراسمس کے خیالات پاک نوشتوں کے الہام اور مجموعے کے متعلق بالکل آزادانہ تھے۔ وہ مقدس یوحنا کے مکاشفہ (بائبل کی آخری کتاب۔ اسلم) کے الہامی ہونے سے منکر تھا۔‘‘
’’لوتھر بائبل کے صحیفوں پر اپنی ہی تمیز کے مطابق حکم لگاتا تھا۔ چنانچہ وہ مقدس ’’یعقوب کے خط‘‘ کے حق میں کہتا تھا کہ وہ تو ’’کوڑا یا بھوسہ‘‘ ہے کیونکہ یہ خط اس کے اس خیال سے کہ آدمی فقط ایمان کے ذریعے سے راست باز ٹھہرتا ہے اختلاف کرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے نزدیک بائبل کے تمام صحیفے یکساں قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ پولوس کی تحریرات کو وہ سب سے افضل سمجھتا تھا۔ اگرچہ اس کے بعض دلائل کی نکتہ چینی کرنے سے بھی نہیں جھجھکتا۔‘‘ (بائبل کا الہام ۔ مصنفہ ڈاکٹر جے پیٹرسن سمائتھ ڈی ڈی ۔ مطبوعہ ۱۹۵۲ء ص ۱۸، ۸۲)
یہودی نظریہ
یہودیوں کی کتابوں کو بھی ۹۰ء میں فلسطین کے مقام حمبنیا میں علماء یہود کی ایک کونسل نے مقدس قرار دیا تھا (میزان الحق ۔ مصنفہ پادری سی جی فانڈر ڈی ڈی ص ۹۶)۔ راقم الحروف کے محدود سے مطالعہ کے مطابق یہودی اپنی کتاب مقدسہ کے مصنفین اور الہام وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تورات بارے ان کا نظریہ خاص ہے۔ ڈاکٹر سمائتھ لکھتے ہیں:
’’یہودیوں کے ربی (علماء۔ اسلم) لوگ موسوسی تحریروں (تورات کی مروجہ پانچ کتابوں۔ اسلم) کی ایسی عزت کرنے لگے کہ آخر کار یہ کہہ اٹھے کہ خدا نے خود آسمان سے یہ کتابیں لکھی ہوئی موسٰیؑ کے حوالہ کی تھیں۔ نہیں بلکہ یہ کتاب ایسی کامل اور ایسی صفات سے موصوف تھی کہ خود یہودا، خدائے قادر اس کے مطالعہ میں ہر روز تین گھنٹے صرف کیا کرتا تھا۔‘‘ (ایضًا ص ۵۰)
مطالعۂ بائبل کے ایک امریکی پروفیسر مارون اردلسن لکھتے ہیں:
’’بنیاد پرست یہودی فی زمانہ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ خدا نے کوہ سینا پر بالکل بنفس نفیس ظاہر ہو کر شریعت دی اس لیے تورات کے الفاظ خدائی ہیں اور مکمل طور پر قطعی ہیں۔‘‘ (A Lion Hand Book: The World's Religions: 1982 - p 292 col 1)
پادری گیرڈ نر تورات بارے یہودی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ
’’ہر لفظ اور ہر حرف میں یکساں الہام ہے۔‘‘ (الہام ۔ مصنفہ پادری کینن ڈبلیو ایچ ٹی گیرڈنر بی اے ۔ مطبوعہ ۱۹۵۸ء ص ۱۵)
عیسائی اختلاف
اب قارئین کرام فاضل پادری صاحب کے اس فرمودہ پر غور فرمائیں:
’’جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسٰیؑ پر توریت شریف ایک کتاب کی صورت میں آسمان سے نازل ہوئی تھی ان کی یہ بات خداوند کی کتاب مقدس کے اصول الہام کے سراسر خلاف ہے کیونکہ آسمان پر پہلے سے توریت کی کتاب کی موجودگی کو تسلیم کرنے کے بعد ہی اس توریت کی کتاب کے بزرگ موسٰیؑ پر آسمان سے نزول کا سوال پیدا ہوتا ہے۔‘‘
معزز پادری صاحب کی جانے بلا کہ مسلمانوں کے نظریۂ الہام پر حملہ کرتے کرتے انہوں نے یہودیوں کے منہ آجانا تھا جو کہ لکھی لکھائی تورات کا نزول ہی نہیں مانتے بلکہ اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ پاک روزانہ تین گھنٹے اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ تورات یہودی کتب مقدسہ (عیسائی بائبل کے پہلے حصہ) کی اصل الاصول ہے، یہودیوں کا سرمایۂ افتخار ہے، ان کی زندگی ہے۔ شریعتِ موسوی اسے ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے اصل اور اولین ماننے والے یہودی ہیں۔ عیسائیوں کی تورات سے دلچسپی اور اس کا تقدس محضزبانی جمعخرچ تک ہی محدود ہے۔ عیسائی اس پر ہزار لعنت بھیجتے ہیں (گلتیوں ۳:۱۳)۔ موجودہ عیسائیت (دراصل پولوسیت) کی تو تعمیر ہی تورات کے قبرستان میں ہوئی ہے۔ یہودی تورات کی عظمت اور الہام بارے جو نظریہ جی چاہے رکھیں، عیسائیوں کو اسے چیلنج کرنے اور ان پر اپنا نظریہ ٹھونسنے کا کیا حق حاصل ہے؟
عیسائی اور لفظی الہام
یہودیوں کی تقلید کبھی عیسائی بھی لفظی الہام کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر سمائتھ کے الفاظ میں:
’’ہم نے بھی بائبل کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ ہم بھی قریباً اس کے حق میں بھی یہی سب باتیں کہہ گزرے ہیں۔ ہم موسٰی اور متی اور پولوس کے واسطے وہ حقوق طلب کرتے ہیں جو شاید کبھی ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں آئے تھے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مگر اس قسم کے باطل توہمات کے ذریعے ہم نے اس کتاب کی فطرتی حسن و خوبی کو گنوا دیا ہے اور ہم نے اس کتاب کو اپنی حماقت سے دشمنوں کے حملوں کے لیے نشانہ بنا دیا ہے کہ بچہ بچہ بھی اگر چاہے تو اس پر ملحدانہ حملہ کرنے کے لیے میدان کھلا پاتا ہے۔‘‘ (ص ۵۰)
قارئین کرام نوٹ فرمائیں کہ پادری صاحب کے دعوٰی کے قطعی برعکس ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں اقوام میں لفظی الہام کا عقیدہ انہی کی زبان ثابت کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ آئیں عیسائیوں کے نظریۂ الہام جسے پادری صاحب ’’خداوند کی کتاب مقدس کا اصول الہام‘‘ کہتے نہیں تھکتے، کی اصل ڈاکٹر سمائتھ ہی کے قلم سے معلوم کریں۔ موصوف لکھتے ہیں:
’’الہام کا خیال فقط یہودیوں اور مسیحیوں میں ہی محدود نہیں ہے۔ قدیم یونانی و رومی مصنف بھی اکثر ’’الٰہی جنون، یا ۔۔، یا خدا سے اٹھائے جانے، یا خدا سے الہام کیے جانے اور پھونکے جانے‘‘ کا ذکر کرتے ہیں۔ فنونِ شریفہ مثلاً سنگ تراشی یا مصوری اور شاعری کی لیاقت، پیشگوئی کی قدرت، عشق و محبت کا جوش اور لڑائی کا تہور، یہ سب باتیں ان فنون کے دیوتاؤں کی طرف منسوب کی جاتی تھیں جو اس وقت اس شخص پر قابو پائے ہوئے سمجھے جاتے تھے۔ یہی الفاظ اور خیالات بعد ازاں مسیحیوں کی مذہبی اصطلاحات میں بھی داخل ہو گئے اور لازمی طور پر ابتدائی کلیسیا کے تصوراتِ الہام پر بھی کسی درجہ تک اپنا اثر ڈالا۔‘‘ (ص ۹۵)
لیجئے ہمارے لیے عیسائی نظریہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ
’’الہام کے معنی ہیں روح القدس کا نفخ یا پھونکنا تاکہ زیادہ روحانی کیفیت یا حالت یا زیادہ گرم جوشی اور گہری محبت پیدا کر دے اور خدا کے مقاصد و منشاء کا گہرا علم و فہم حاصل ہو یا دیگر قابلیتوں کو جن کے استعمال کی الہامی شخص کو اپنے منصبی کام کے سرانجام کرنے کے لیے ضرورت تھی زیادہ تیز اور طاقت ور کر دے۔‘‘ (ص ۹۰)
اب جس مجموعہ کتب کا کوئی سر منہ نہ ہو، اس میں عجیب و غریب اور ناقابلِ یقین و ایمان باتیں لکھی ہوں، اس کی کتابیں انفرادی صوابدید کی زد میں ہوں، انہیں الہامی ماننے سے انکار کیا جا رہا ہو، ان کتابوں کے لفظی الہام کو کون مانے گا؟ ذرا ایک حوالہ مطالعہ فرمائیں۔ بائبل کی کتاب ایوب میں لکھا ہے:
’’اس کا ایوبؑ پر غصہ بھڑکا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا سے زیادہ صادق ٹھہرایا تھا اور اس کا غصہ تینوں دوستوں پر بھی بھڑکا اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہ تھا اور انہوں نے خدا کو مجرم ٹھہرایا تھا‘‘۔ (ایوب ۳۳: ۲، ۳۔ رومن کیتھولک اردو ترجمہ بائبل۔ کلام مقدس مطبوعہ سوسائٹی آف سینٹ پال روما ۱۹۵۸ء)
چنانچہ عیسائیوں کو لفظی الہام کا نظریہ مجبورًا چھوڑنا پڑا کہ وہ بائبل کو ڈوبے لیے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر سمائتھ بصد حسرت و یاس لکھ گئے:
’’پاک نوشتوں (بائبل کی کتابوں۔ اسلم) کے ہر ایک طرح کے تفصیلی امور میں کامل طور پر بے خطا ہونے پر اصرار کرنا فقط ایک غیر ضروری اور بے سند بات ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ماننا الہام کے عقیدہ کو سخت معرض خطر میں ڈالتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو ۔۔۔ فرانس کے مشہور مصنف اور فصیح البیان رینان کو کس چیز نے ملحد بنا دیا؟ یہی بات کہ الہام کے عقیدۂ سہو و خطا سے بریت کے عقیدہ کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ چارلس بریڈلا کو کس چیز نے بائبل کا دشمن بنا دیا؟ یہ کہ پادری جس نے اسے مستقیم ہونے کے لیے تیار کیا اس نے اس ذی فہم لڑکے کے سوالات کو جو وہ الہام کے مسئلہ پر کرتا تھا اپنی تنگ خیالی کی وجہ سے زجر و توبیخ کے ساتھ رد کر دیا اور ان کا کچھ تسلی بخش جواب نہ دیا۔
ناظرین! آپ بھی کئی لوگوں سے واقف ہوں گے جن کا ایمان اسی قسم کی تعلیمات کے سبب سے زائل ہو گیا ہے۔ چند ماہ ہوئے خود میرے ذاتی تجربے میں بھی یہ امر آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے ایک بڑے گاڑھے دوست کے ایمان پر اسی قسم کی غلط تعلیم نے پانی پھیر دیا۔ یقین جانو وہ لوگ بائبل کے نادان دوست ہیں جو الہام کو اس قسم کے سوالات کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں۔ جب مذہبی معلموں کی جماعت میں ایسے اشخاص موجود ہوں جو یہ کہیں کہ ایک ذرا سی غلطی کے ثابت ہونے سے بائبل کا الہامی ہونا مردود ٹھہرے گا جبکہ لفظوں کے صاف صاف معنوں کو کھینچ تان کر ذرا ذرا سے اختلافات کو تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کے علمی امور کے متعلقہ باتوں کو زمانۂ حال کی تحقیقات اور دریافتوں سے ملایا جاتا ہے تو اس سے بائبل کو کچھ نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس کی جان عذاب میں پھنستی ہے۔ ایسی کتابوں کو پڑھ کر خواہ مخواہ یہ خیال پیدا ہو گا کہ گویا ہماری نجات کا مدار اسرائیلیوں کی ادنٰی علمی واقفیت کی صحت پر ہے یا یہ کہ ہمارا مذہب معرض خطر میں ہے۔‘‘ (صفحات ۱۴۶ ۔ ۱۴۷)
عیسائی نظریۂ الہام کی تشریح کی جا چکی ہے کہ عیسائی علماء کی کونسلوں کا مرہونِ منت ہے۔ پادری صاحبان جس کتاب کو مناسب سمجھیں ’’الہام‘‘ کا سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیں۔ عملی صورت یہی ہے، باقی سب لفاظی ہے، آئیں بائیں شائیں کرنا اور حجتیں کاٹنا ہے۔ عیسائی اتنا اتراتے جو پھرتے ہیں کیا کوئی مائی کا لال عیسائیوں کا تسلیم شدہ ’’خداوند کی کتابِ مقدس کا اصولِ الہام‘‘ خداوند کی کتاب مقدس میں سے دکھا سکے گا؟ صاحبو! سجے سجائے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر ’’خداوند کی کتابِ مقدس کے اصولِ الہام‘‘ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دینا اور بات ہے جبکہ آب و گل کی اس بستی رستی دنیا میں ’’خداوند کی کتابِ مقدس کے اصولِ الہام‘‘ کو نباہنا اور ثابت کرنا اور بات۔
لگے ہاتھوں عیسائی بھائی یہ بھی بتا دیں کہ اگر انہوں نے نظریات کی بے آب و گیاہ وادیوں میں یونہی دھکے کھانے اور ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرنا ہے تو پھر تثلیثِ اقدس کے دوسرے اقنوم مسیح خداوند کے اس قول کہ ’’دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں‘‘ (انجیل متی آیت آخر) اور تیسرے اقنوم روح القدس خداوند کا مسیحیوں کو تعلیم دینے اور رہنمائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ (مسیحی علم الٰہی کی تعلیم ۔ مصنفہ پادری لوئیس برک ہاف وکلف اے سنگھ ۔ مطبوعہ ۱۹۸۲ء ص ۱۳۶)۔ یارو! کچھ تو بولو، سانپ ہی کیا سونگھ گیا؟ جو کچھ تم نے بولنا ہے روح القدس تمہیں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ (مرقس ۳: ۱۱)
مئی کے شمارہ میں پادری فنڈر کو کیتھولک لکھا گیا ہے حالانکہ پادری صاحب پروٹسٹنٹ فرقہ سے متعلق تھے۔ اپوکریفہ کی بحث میں بقلم خود لکھتے ہیں ’’ہم پروٹسٹنٹ مسیحی عہدِ عتیق کی عبرانی کتبِ دین کو مانتے ہیں‘‘ (میزان الحق ص ۱۴۴)۔ امید ہے کہ یہ چند حروف بغرضِ تصحیح کافی رہیں گے۔‘‘
نسخ و تحریف پر مولانا کیرانویؒ اور ڈاکٹر فنڈر کا مناظرہ
محمد عمار خان ناصر
(یہ مناظرہ امام المناظرین مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ اور نامور عیسائی مناظر پادری ڈاکٹر سی جی فنڈر کے درمیان ۱۲۷۰ھ کے دوران آگرہ میں ہوا۔ مناظرہ اردو زبان میں ہوا تھا جو دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے عربی ترجمہ کو سامنے رکھ کر اسے نئے سرے سے مرتب کیا گیا ہے۔ مناظرہ کے لیے پانچ موضوعات طے ہوئے تھے: (۱) نسخ (۲) تحریف (۳) تثلیث (۴) رسالتِ محمدیؐ (۵) حقانیتِ قرآن۔ مگر صرف دو دن پہلے دو موضوعات پر مناظرہ ہوا اور تیسرے دن پادری فنڈر یا ان کے کسی ساتھی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر وزیرخان مرحوم نے اس مناظرہ میں مولانا کیرانویؒ کی معاونت کی جو انگریزی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور عیسائیت کے موضوعات پر خود بھی کامیاب مناظر تھے، جبکہ پادری فرنچ اس مناظرہ میں پادری فنڈر کے معاون تھے — ناصر)
مناظرہ کا پہلا دن
نسخ کی بحث
پہلے روز مناظرہ ’’نسخ‘‘ کے موضوع پر شروع ہوا اور پادری فنڈر نے یوں بحث کا آغاز کیا:’’حاضرین! یہ مباحثہ فاضل مولوی صاحب کی دعوت پر منعقد ہو رہا ہے اور میں نے اس کو انہی کی دعوت پر قبول کیا ہے ورنہ مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ میرا ارادہ ہے کہ مذہب مسیحی کی حقانیت کے دلائل اہلِ اسلام کے آگے رکھوں۔ یہ مناظرہ نسخ، تحریف، تثلیث، اثباتِ نبوت محمد اور حقانیتِ قرآن پر ہو گا۔ پہلے تین مسائل میں بندہ مجیب اور مولوی صاحب معترض ہوں گے اور آخری دو مسائل میں اس کے برعکس۔‘‘
یہ کہہ کر فنڈر بیٹھ گئے، مولانا رحمت اللہ کھڑے ہوئے اور کہا:’’آپ نے اپنی کتاب میزان الحق باب اول فصل دوم میں دو باتیں لکھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں:
اول: نسخہ مطبوعہ ۱۸۵۰ بزبان اردو کے صفحہ ۱۴ پر لکھا کہ ’’قرآن اور مفسرین کا دعوٰی ہے کہ جیسے زبور کے نزول سے تورات اور انجیل کے نزول سے زبور منسوخ ہو گئی اسی طرح انجیل بھی قرآن کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہے۔‘‘
دوم: صفحہ ۲۰ پر لکھا کہ ’’کسی محمدی کے پاس اس دعوٰی کی کوئی دلیل نہیں کہ زبور تورات کی ناسخ اور انجیل دونوں کی ناسخ ہے۔‘‘
آپ نے زبور کے نزول سے تورات کے منسوخ ہونے کا دعوٰی غلط طور پر اہلِ اسلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ قرآن اور مفسرین میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا بلکہ اس کے برعکس ’’تفسیر عزیزی‘‘ میں بقرہ ۸۷ کے تحت لکھا ہے کہ ’’ہم نے موسٰیؑ کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجے مثلاٍ یوشعؑ، الیاسؑ، الیسعؑ، سموئیلؑ، داوٗدؑ، سلیمانؑ، اشعیاءؑ، ارمیاءؑ، یونسؑ، عزیرؑ، خرقی ایلؑ، زکریاؑ، اور یحٰیؑ وغیرہ۔ تقریباً چار ہزر تھے اور سب کے سب شریعت موسوی کے ماتحت تھے اور ان کی بعثت سے مقصود شریعت موسوی کے احکام کا اجراء تھا جن پر بنی اسرائیل کی سستی اور کاہلی اور ان میں سے علماء سوء کی تحریفات کے باعث عملدرآمد نہ ہو رہا تھا۔‘‘
اور ’’تفسیر حسینی‘‘ میں لکھا ہے (تحت نساء ۱۶۳) ’’ہم نے داؤد کو ایک کتاب دی جس کا نام زبور تھا جو حمد و ثنا پر متضمن اور احکام و اوامر سے خالی تھی کیونکہ داؤد علیہ السلام شریعت موسوی ہی کے پیرو تھے۔‘‘ اور اسی طرح دوسری اسلامی کتب میں لکھا ہے۔
فنڈر: آپ انجیل کو منسوخ مانتے ہیں یا نہیں؟
مولانا: ہم انجیل کو ان معنوں میں منسوخ مانتے ہیں جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے۔ فی الحال صرف یہ ہے کہ آپ نے دونوں عبارتیں اپنی کتاب میں غلط لکھی ہیں۔
فنڈر: یہ میں نے ان لوگوں سے سنی ہیں جن کے ساتھ مجھے بحث و مباحثہ کا اتفاق ہوا ہے۔
مولانا: یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ سنی سنائی باتیں قرآن اور مفسرین کی جانب منسوب کر دیتے ہیں؟ یہ یقیناً غلط ہے۔
فنڈر: ٹھیک ہے۔
مولانا: کیا آپ مسلمانوں کے ہاں اصطلاحی نسخ کے مفہوم سے واقف ہیں؟
فنڈر: بتائیں۔
مولانا: ہمارے نزدیک نسخ صرف اوامر و نواہی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ ’’النسخ یعترض علی الاوامر والنواھی‘‘ مطلب یہ ہے کہ قصص و واقعات یا امور عقلیہ قطعیہ (مثلاً یہ کہ اللہ موجود ہے) یا امور حسیہ (مثلاً دن کی روشنی اور رات کی تاریکی وغیرہ) میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ اور امر و نواہی میں بھی تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ ضروری ہے کہ اوامر و نواہی ایک ایسے حکم عملی کے ساتھ متعلق ہوں جس کے وجود و عدم دونوں کا احتمال ہو۔ پس حکم واجب مثلاً ایمان باللہ اور حکم ممتنع مثلاً شرک و کفر وغیرہ محل نسخ نہیں۔ اور عملی حکم جو احتمال وجود و عدم دونوں کا رکھتا ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں: (۱) مؤبد، یعنی وہ حکم جس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہو جیسے ’’ولا تقبلوا لھم شھادۃ ابدًا‘‘ (النور) میں متہمین کی شہادت کی عدم قبولیت! یہ بھی نسخ کا محل نہیں۔ (۲) غیر مؤبد، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مؤقت، یعنی وہ حکم جس کی مدتِ انتہا بیان کر دی گئی ہو۔ مثلاً ’’فاعفوا واصفحوا حتٰی یاتی اللہ بامرہ‘‘ (مائدہ) میں عفو کا حکم موقت ہے۔ اتہیان اللہ بالامر کے ساتھ یہ قسم محل نسخ کا نہیں جب تک کہ مقررہ وقت پورا نہ ہو جائے۔ (۲) غیر مؤقت، یعنی حکم مطلق، یہ محل نسخ کا ہے۔
اب نسخ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالٰی جانتے تھے کہ یہ حکم مکلفین پر فلاں وقت تک باقی رہے گا پھر منسوخ ہو جائے گا۔ جب وہ وقت آ گیا کہ دوسرا حکم پہلے حکم کے مخالف بھیج دیا جائے، اس سے پہلے حکم کی انتہا معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ پہلے حکم میں اس کے مقررہ وقت کا بیان نہیں تھا لہٰذا دوسرے حکم کے آجانے پر ہمارا ناقص ذہن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ پہلے حکم کی تغییر ہے، حالانکہ فی الحقیقت یہ تغییر نہیں بلکہ اس کی انتہا کا مظہر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ مالک غلام کو ایک خاص خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس سے یہ خدمت میں فلاں وقت تک لوں گا۔ جب وہ مدت گزر جاتی ہے تو مالک اس کو کوئی دوسری خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خادم کے گمان میں تغییر نہیں بلکہ دراصل اس کی پہلی خدمت کی انتہا کا بیان ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ حاکمِ وقت اہلِ دربار کو گرمیوں کے موسم میں حکم دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت حاضر ہوں اور اس کے اپنے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ حکم سردیوں کے آنے تک رہے گا، لیکن وہ درباریوں کو بتاتا نہیں۔ اس سے اہلِ دربار سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر جب سردیاں آجاتی ہیں تو حاکمِ وقت اہلِ دربار کو کسی اور وقت میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ درباریوں کے خیال میں میں یہ پہلے حکم کی تغییر لیکن حاکم کے مطابق حکمِ سابق کی انتہا کا بیان ہے۔
پس اہل اسلام کے ہاں نسخ اصطلاحی ایک ایسے حکمِ عملی کی مدت انتہا کے بیان کو کہتے ہیں جو وجود و عدم دونوں کا محتمل ہو اور ہمارے خیال میں وہ ہمیشہ کے لیے ہو (حالانکہ دراصل ایسا نہ ہو)۔
فنڈر: اس لحاظ سے تمہارے نزدیک انجیل کا کون سا حکم منسوخ ہے؟
مولانا: مثلاً حرمتِ طلاق کا حکم۔ انجیل میں ہے کہ طلاق دینا حرام ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔
فنڈر: کیا تمہارے نزدیک ساری انجیل منسوخ نہیں؟
مولانا: نہیں! کیونکہ انجیلِ مرقس میں لکھا ہے: ’’اے اسرائیل سن خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔‘‘ (آیات ۲۹ تا ۳۱) ہمارے ہاں یہ دونوں حکم باقی ہیں۔
فنڈر: انجیل ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتی کیونکہ مسیح نے کہا ہے ’’آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔‘‘ (لوقا ۲۱ : ۳۳)
ڈاکٹر وزیر خان (مولانا کے معاون خصوصی) : یہ قول عام نہیں ہے بلکہ ان امور کے ساتھ خاص ہے جن کا بیان مسیحؑ نے اس سے ماقبل کیا ہے۔
فنڈر: نہیں مسیح کا قول عام ہے خاص نہیں۔
ڈاکٹر صاحب: ڈی آئلی اور رچرڈمنٹ کی تفسیر انجیل متی ۲۴: ۳۵ کے ذیل میں دیکھئے، لکھا ہے ’’پادری بیرس صاحب کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جن امور کی خبر میں نے تمہیں دی ہے وہ یقیناً واقع ہوں گے، اور دین استاین ہوب نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اگرچہ آسمان اور زمین دوسری اشیاء کی بہ نسبت تغیر و تبدل کے قابل نہیں ہیں لیکن یہ بھی ایسے محکم نہیں ہے جتنا ان امور کا وقوع جن کی میں نے تمہیں خبر دی ہے۔ یہ دونوں زائل ہو جائیں گے لیکن میری بتائی ہوئی باتیں نہ ٹلیں گی بلکہ جو کچھ میں نے تمہیں ابھی بتا دیا ہے اس سے کچھ بھی متجاوز نہ ہو گا۔‘‘
فنڈر: ان دونوں کا قول ہمارے دعوی کے منافی نہیں کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری انسانی واقعات کی بابت خبریں ٹل جائیں گی اور باقی نہ ٹلیں گی۔
ڈاکٹر صاحب: اس بات کا مذکورہ آیت سے کیا تعلق؟
فنڈر: نہیں! مسیح کا قول عام ہی ہے۔
ڈاکٹر صاحب: ہم نے اپنے حق میں دو گواہ پیش کیے ہیں اور آپ ہیں کہ بے دلیل اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔
فنڈر: پطرس کے پہلے خط کے باب کی آیت ۲۳ یوں ہے: ’’کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو‘‘۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا اور منسوخ نہیں ہو گا۔
مولانا رحمت اللہ: پرانے عہد نامہ کی کتاب یسعیاہ میں بھی یونہی لکھا ہے: ’’ہاں گھاس مرجھا جاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔‘‘ (۴۰: ۸)۔ اگر اس قول سے عدمِ نسخ ہی مراد ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات کے احکام منسوخ نہیں ہوئے۔ حالانکہ ان میں سے کئی احکام شریعتِ عیسوی میں منسوخ ہوئے۔
فنڈر: ہاں تورات منسوخ ہے لیکن ہم تورات کی بات نہیں کرتے۔
مولانا: بھئی ہمارا مقصود یہ ہے کہ پطرس کا کلام بھی وہی مفہوم رکھتا ہے جو یسعیاہ کا۔ اور جب یسعیاہ کے قول سے عدمِ نسخ مراد نہیں تو پطرس کے قول سے کیسے ہو سکتا ہے؟
فنڈر: میں نے پطرس کا قول سند کے قول پر نقل کیا ہے، دلیل ہماری مسیح کا قول ہی ہے (یعنی یہ کہ میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی)۔
مولانا: ہم پہلے دلیل دے چکے ہیں کہ وہ قول مخصوص ہے تاہم ’’نہ ٹلنے‘‘ سے مراد بھی عدمِ نسخ نہیں ہے۔ انجیل متی ۵: ۱۸ یوں ہے: ’’میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے‘‘۔ اگر نہ ٹلنے سے عدمِ نسخ ہی مراد ہے تو تورات کے احکام کیوں منسوخ ہوئے؟
فنڈر: ہم تورات کی بات نہیں کرتے۔
ڈاکٹر وزیر خان: آپ توریت کی بات کریں نہ کریں، ہمارے نزدیک دونوں عہد نامے برابر ہیں۔ نیز آپ نے اپنی کتاب میزان الحق باب اول فصل دوم میں لکھا ہے کہ انجیل اور عہد قدیم ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتے۔
فنڈر: میں نے یہ بات وہاں لکھی ہے۔ یہاں پر میری بحث صرف انجیل میں ہے۔
ڈاکٹر صاحب: حواریوں نے اپنے زمانے میں تورات کے چار احکام (بتوں کی قربانیوں، خون، گلا گھونٹے ہوئے جانور، اور زنا کی حرمت) کے علاوہ تمام احکام منسوخ قرار دیے تھے یعنی صرف چار احکام باقی رہ گئے تھے۔ حالانکہ اب صرف زنا کی حرمت باقی رہ گئی ہے، باقی تین چیزیں تو اب آپ کے نزدیک حلال ہیں۔ کیا یہ انجیل میں نسخ نہیں؟
فنڈر: ان اشیاء کی حرمت ہمارے نزدیک مختلف فیہ ہے۔ بعض کے نزدیک منسوخ ہیں اور بعض کے نزدیک نہیں۔ لیکن بتوں کی قربانیوں کو ہم اب تک حرام کہتے ہیں۔
مولانا رحمت اللہ: آپ کو روا نہیں ہے کہ آپ بتوں کی قربانی کو حرام کہیں کیونکہ آپ کے مقدس بزرگ پولس نے کہا: ’’مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔‘‘ (رومیوں ۱۴: ۱۴)۔ اور کہتا ہے کہ ’’پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں (ططس ۱: ۱۵)۔
فنڈر: (حیران ہو کر) ہمارے بعض علماء نے ان آیات کے پیشِ نظر ان اشیاء کی حلت کا فتوٰی دیا ہے۔
مولانا: مسیح نے حواریوں کو پہلے یہ حکم دیا: ’’غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کی طرف جانا‘‘۔ (متی ۱۲: ۵، ۶)۔ اور کہا: میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔‘‘ (۱۵: ۲۴)۔ یعنی اپنی نبوت کو محدود قرار دیا لیکن بعد میں حکم دیا کہ ’’تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔‘‘ (مرقس ۱۶: ۱۵)
فنڈر: ہاں لیکن یہاں مسیح خود اپنے قول کا ناسخ ہے۔
مولانا: اس قدر تو ثابت ہو گیا کہ مسیح کے کلام میں نسخ جائز ہے اور اس نے خود اپنے قول کو منسوخ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آسمانی باپ زیادہ قادر ہے کہ اپنے کلام کو منسوخ کرے کیونکہ انجیل میں قولِ مسیح ہے کہ ’’باپ مجھ سے بڑا ہے‘‘۔ (یوحنا ۱۴: ۲۸)۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آسمانی باپ نے اپنے کلام کو منسوخ کیا نہ کہ حضرت محمدؐ نے بذاتِ خود۔ اور باقی آپ کا استدلال مسیح کے اس قول سے کہ ’’میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی‘‘ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ قول خاص ہے۔ نیز ’’نہ ٹلنے‘‘ سے عدمِ نسخ مراد نہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور خدشہ کی وضاحت بھی کر دوں جو آپ کے ایک قول کے بارے میں میرے ذہن میں موجود ہے۔
فنڈر: فرمائیں۔
مولانا: آپ نے اپنی کتاب میزان الحق باب اول فصل دوم میں لکھا ہے کہ ’’انجیل اور عتیق کی کتابوں میں نسخ کا دعوٰی دو وجہوں سے باطل ہے۔ اول: اگر نسخ کے فلسفہ کو مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اولاً خدا نے اپنے ظن کے مطابق تورات کے ذریعے ایک اچھا و اعلٰی حکم دیا لیکن وہ اچھا ثابت نہ ہوا تو اس سے بھی افضل انجیل میں دیا لیکن وہ بھی اچھا ثابت نہ ہوا تو اس سے بھی افضل انجیل میں دیا۔ اس کا حال بھی پہلوں جیسا ہوا تو قرآن میں اس سے اعلٰی و افضل حکم دیا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے تو العیاذ باللہ اللہ تعالٰی کی حکمت و قدرت کا بطلان لازم آئے گا اور خدا کا انسانی بادشاہ کی طرح ناقص العقل اور عدیم الفہم ہونا لازم آئے گا حالانکہ یہ صفاتِ الٰہی نہیں بلکہ انسانی ہیں۔ دوم: اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کا مقصودی حکم صرف قرآن میں پایا جاتا ہے تو لازم آئے گا کہ خدا نے پہلے جان بوجھ کر انسان کو ناقص اور بے فائدہ چیز دی اور یہ ذات باری تعالٰی کی نسبت محال ہے۔‘‘
آپ نے کہنے کو تو کہہ دیا لیکن مسلمانوں کے اصطلاحی نسخے کے پیشِ نظر یہ اعتراضات وارد نہیں ہو سکتے، البتہ پولس پر یہ الزام ضرور وارد ہوتا ہے کیونکہ اس نے کہا ’’پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا۔‘‘ (عبرانیوں ۷: ۱۸)۔ اور کہتا ہے کہ ’’اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا ۔۔۔ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا۔ جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔‘‘ (عبرانیوں ۸: ۸۔۱۳)
ان آیات میں پولس نے تورات کو ضعیف، بے فائدہ، عیب دار اور مٹنے کے قریب پرانی و بوسیدہ بتایا ہے۔
فنڈر نے کوئی جواب نہ دیا۔
مولانا: میزان الحق کے یہ چند صفحات جو آپ نے نسخ کے رد میں لکھے ہیں یہ واجب الاخراج ہیں کیونکہ ان میں مذکور امور کو غلط طور پر ہماری طرف منسوب کیا گیا ہے۔
پانچ فرنچ (فنڈر کا معاون خصوصی): ہم نے گذشتہ مناظرہ میں کہا تھا کہ تورات کے احکام اس لیے منسوخ ہوئے کہ ان کی حیثیت مسیح کے مقابلہ میں سائے کی سی تھی، ان کا نسخ مناسب تھا کیونکہ مسیح نے ان کی تکمیل کی۔ البتہ وہ بشارات جو مسیح کے حق میں ہیں غیر منسوخ ہیں کیونکہ انجیل میں لکھا ہے: ’’کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک طرح کی قربانیوں ہے جو ہر سال بلاناغہ گزارنی جاتی ہیں پاس آنے والوں کا ہرگز کامل نہ کر سکتی ورنہ ان کا گذراننا موقوف نہ ہو جاتا؟ کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کر دے اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔‘‘ (عبرانیوں ۱۰: ۱۔۶)
یعنی خدا شریعت پر راضی نہ تھا بلکہ شریعت صرف مسیح کی طرف اشارہ اور راہنما ہیں اور اس کی آمد پر ان کی تکمیل ہو گئی (۱)۔ چونکہ مسیح سے پہلے کی کتب میں مسیح کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے اس لیے مسیح ان کا ناسخ ہو سکتا ہے لیکن انجیل میں کسی کی جانب ایسا کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا لہٰذا انجیل کا ناسخ کون ہو سکتا ہے؟
ڈاکٹر وزیر خان: آپ نے یہ جو کہا ہے کہ کتبِ عہدِ عتیق میں مسیح کی بابت اشارہ و بشارت پائی جاتی ہے اس لیے مسیح ناسخ ہو سکتا ہے، اس لیے غلط ہے کہ مسیح کی آمد سے قبل بھی کچھ احکام منسوخ ہوئے ہیں۔
فرنچ: مثلاً کون سا حکم؟
ڈاکٹر صاحب: مثلاً ذبح کرنا ممنوع تھا (احبار باب ۱۷) لیکن پھر جائز ہو گیا (استثناء ۱۲: ۱۵۔۲۰۔۲۲)۔ اور مفسر ہورن نے اپنی تفسیر مطبوعہ ۱۸۲۲ء جلد اول ص ۶۱۹ پر اقرار کیا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہوا ہے اور تصریح کی ہے کہ اس کا نسخ مصر سے خروج اور فلسطین میں دوخل کے درمیانی چالیس سال میں وقوع پذیر ہوا۔
فرنچ: خاموش صامت۔
ڈاکٹر صاحب: تاحال ہم نے امکانِ نسخ پر بحث کی ہے اور انجیل میں وقوعِ نسخ پر ہم اثباتِ رسالتِ محمدؐ کے موقعہ پر بحث کریں گے۔ فی الحال فقط امکانِ نسخ کو ثابت کیا ہے جس کا پادری صاحبان نے بالعموم اور پادری فنڈر صاحب نے بالخصوص میزان الحق میں انکار کیا ہے۔
فنڈر: ہاں ہمارے نزدیک بھی امکان و وقوع میں فرق ہے۔
اس پر نسخ کی بحث مکمل اور تحریف کی بحث شروع ہو گئی۔
تحریف کی بحث
مولانا رحمت اللہ نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے نزدیک تحریف کس کو کہتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق ثبوت مہیا کریں۔ فنڈر نے کوئی واضح جواب نہ دیا تو مولانا نے کہا، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہر ایک لفظ اور جملہ الہامی ہے؟
فنڈر: ہم ہر لفظ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں کاتب کی غلطیوں کا اعتراف ہے۔
مولانا: میں سہوِ کاتب سے قطع نظر کرتا ہوں۔ دوسرے الفاظ کے بارے میں بتائیے!
فنڈر: ہم الفاظ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔
مولانا: یوسی بیس مؤرخ نے اپنی کتاب کے باب ۱۸ میں کہا ہے کہ عیسائی عالم ’’جسٹن شہید نے طریفو یہودی کے ساتھ مناظرہ میں چند بشارات ذکر کر کے دعوٰی کیا ہے کہ یہودیوں نے ان کو کتب مقدسہ سے ساقط کر دیا ہے (۲)۔‘‘ اور مفسر والٹن نے اپنی تفسیر جلد سوم ص ۳۲ میں لکھا ہے ’’اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عبارات جن کے کتب مقدسہ سے اسقاط کا دعوٰی جسٹن نے طریفو کے ساتھ مناظرہ میں کیا تھا وہ جسٹن اور امینیوس کے زمانہ میں عبرانی و یونانی اور دیگر نسخوں میں موجود تھیں اگرچہ آج کل ان میں نہیں پائی جاتیں۔ خصوصاً وہ عبارت جس کے یرمیاہ کی کتاب میں مذکور ہونے کا دعوٰی جسٹن نے کیا تھا اور سلبر جیسی اور ڈاکٹر کریب نے لکھا ہے کہ جب پطرس نے اپنے پہلے خط کے باب ۴ کی آیت نمبر ۶ لکھی تو اس کے خیال میں یہ بشارت موجود تھی۔‘‘
اور مفسر ہورن اپنی تفسیر مطبوعہ ۱۸۲۲ء جلد ۴ ص ۶۲ پر لکھتا ہے کہ ’’جسٹن نے طریفو کے ساتھ مقابلہ میں دعوٰی کیا کہ غدرا نے لوگوں کو کہا تھا کہ ’’عید قسم کا کھانا ہمارے نجات دہندہ خدا کا کھانا ہے۔ پس اگر تم نے خدا کو اس کے کھانے سے افضل سمجھا اور اس پر ایمان لے آئے تو زمین ویران نہ رہے گی۔ اور اگر تم نے اس کی بات نہ سنی تو غیر قومیں تم سے استہزاء کریں گی اور تم خود اس کا سبب ہو گے۔ اور وائی ٹیکر نے کہا ہے کہ یہ عبارت غالباً عزرا ۶: ۲۲ اور ۶: ۲۱ کے درمیان کی تھی اور ڈاکٹر کلارک نے جسٹن کی تصدیق کی ہے۔‘‘
پس ان تمام عبارات سے ظاہر ہے کہ جسٹن یہودیوں کو تحریف کا ملزم گردانتا تھا اور ارمینیوس، کریب، سیلر جیسی، وائی ٹیکر، ای کلارک اور واٹسن وغیرہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ عبارات اس وقت عبرانی و یونانی نسخوں میں موجود تھیں لیکن آج نہیں ہیں۔ یا تو جسٹن اپنے دعوٰی میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر سچا ہے تو تحریف کا اثبات ہوتا ہے۔ اور اگر جھوٹا ہے تو ایک بڑا عیسائی عالم اپنی طرف سے عبارات اختراع کر کے ان کو کتبِ مقدسہ کا جزو قرار دیتا ہے۔
فنڈر: جسٹن ایک ہی آدمی ہے اور وہ بھول گیا تھا۔
مولانا: ہنری واسکاٹ کی تفسیر جلد اول میں تصریح ہے کہ ’’سینٹ آگسٹائن (مشہور عیسائی عالم و فلسفی) یہودیوں پر تحریف کا الزام لگاتا تھا کہ انہوں نے عبرانی نسخہ میں تحریف کی ہے اور جمہور علماء بھی یہی کہتے ہیں اور ان کا اتفاق ہے کہ یہ تحریف ۱۳۰ء میں کی گئی ہے۔
فنڈر: ہنری واسکاٹ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے علاوہ بھی کئی مفسرین ہیں۔
مولانا: انہوں نے اپنی نہیں جمہور علماء کی رائے بھی بیان کی ہے۔
فنڈر: مسیح نے کتب عہد عتیق کے حق میں شہادت دی ہے (۳) اور اس کی شہادت سے بڑی کوئی شہادت نہیں۔ چنانچہ انجیل یوحنا ۵: ۴۶ یوں ہے: ’’اگر تم موسٰی کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا‘‘۔ اور انجیل لوقا ۲۴: ۲۷ یوں ہے: ’’پھر موسٰی سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں‘‘۔ اور انجیل لوقا ۱۶: ۳۱ یوں ہے: ’’اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسٰی اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔‘‘
ڈاکٹر وزیر خان: تعجب ہے کہ آپ اسی کتاب سے استدلال کر رہے ہیں جس کی صحت و عدمِ صحت پر بحث ہو رہی ہے۔ جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کتاب سے آپ کا استدلال درست نہیں ہے۔ تاہم آپ نے جو آیات ذکر کی ہیں ان سے صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتابیں مسیح کے زمانہ میں موجود تھیں لیکن الفاظ کا تواتر اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی تائید بیلی نے اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۵۰ء لندن قسم سوم باب شسشم میں کی ہے اور بیلی کی کتاب کو آپ نے اپنی کتاب ’’حل الاشکال‘‘ میں مستند شمار کیا ہے۔
فنڈر: اس مقام پر ہم بیلی کی بات نہیں مانتے۔
مولانا رحمت اللہ: اگر تم بیلی کی بات نہیں مانتے تو ہم تمہاری نہیں مانتے، ہم تو بیلی کی ہی مانتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب: یعقوب کے عام خط باب ۵ آیت ۱۱ میں ہے: ’’تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا‘‘۔ اس آیت میں ایوب کی کتاب کے حق میں شہادت دی گئی ہے (۴) لیکن اس کے باوجود اہلِ کتاب میں ہمیشہ جھگڑا رہا ہے کہ یہ ایوب نام کا کوئی شخص تھا بھی یا یہ محض ایک کہانی ہی ہے۔ مشہور یہودی عالم ربی ممانی دینہ اور عیسائی علماء ولکلرک، میکاملیس، سملر، اسٹاک وغیرہ اس کو باطل اور فرضی قصہ مانتے ہیں۔
فنڈر: ہمارے نزدیک یہ اصلی ہے اور اگر مسیح کی شہادت میں داخل ہے تو الہامی بھی ہے۔
ڈاکٹر صاحب: پولس، تلمیتھس کے نام اپنے دوسرے خط ۳: ۸ میں لکھتا ہے کہ ’’یاناس‘‘ اور ’’ویمپراس‘‘ نے موسٰی کی مخالفت کی۔ نامعلوم پولس نے یہ دونوں نام کہاں سے دیکھے، شاید جعلی کتاب سے کیونکہ توریت میں ان کا ذکر نہیں۔
فنڈر: ہماری بحث جعلی کتابوں میں نہیں ہے۔ میں نے مسیح کا قول عہد عتیق کی کتب کے حق میں نقل کیا ہے، جب تک انجیل کی تحریف ثابت نہیں ہو جاتی مسیح کی شہادت کافی و وافی ہے۔
مولانا رحمت اللہ: ہم دونوں عہدوں کے مجموعہ کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر فرق ہے تو آپ کے نزدیک۔ آپ ایک جزء کے حق میں دوسرے جزء سے استدلال ہمارے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ جب تک آپ دونوں عہدوں کا محرف نہ ہونا ثابت نہ کر لیں تب تک آپ ان سے ہم پر دلیل نہیں لے سکتے۔
فنڈر: میں نے مسیح کا قول کتب عہد عتیق کے حق میں نقل کیا ہے، آپ انجیل کی تحریف کا اثبات کریں۔
ڈاکٹر وزیر خان: لیجئے! لکھا ہے: ’’پس سب پشتیں ابرہام سے داؤد تک چودہ پشتیں ہوئیں اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پشتیں ہوئیں۔‘‘ (انجیل متی ۱: ۱۷)۔ ان آیات میں دعوٰی ہے کہ گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پشتیں ہیں حالانکہ ذکر صرف تیرہ کا ہے۔
فنڈر: کیا ایسا تمام نسخوں میں ہے؟
ڈاکٹر صاحب: سب نسخوں میں ہے یا نہیں ہمیں علم نہیں لیکن یہ بہرحال غلطی ہے۔
فنڈر: غلطی اور چیز ہے اور تحریف اور۔
ڈاکٹر صاحب: اگر انجیل الہامی ہے تو اس میں غلطی کیسی؟ لازماً یہ تحریف کا نتیجہ ہے۔ اور اگر الہامی نہیں ہے تو؟
فنڈر: تحریف تب ہی ثابت ہو گی جب ایک آیت کا ۔۔۔۔ قدیم نسخہ میں فقدان یا وجود ہو اور جدید میں وجود یا فقدان۔
ڈاکٹر صاحب: یوحنا کے پہلے خط کے باب ۵ آیات ۷۔۸ کو پیش کیا (۵)۔
فنڈر: ہاں یہاں تحریف ہوئی ہے اور اسی طرح ایک دو اور جگہوں میں۔
جب جج سمتھ نے یہ سنا تو اس نے پادری فرنچ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پادری فرنچ نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے ہورن وغیرہ کی کتابوں سے سات آٹھ جگہوں میں تحریف کا اقرار دکھایا ہے۔
پادری فرنچ: پادری فنڈر بھی چھ سات جگہوں میں تحریف کا وقوع مانتے ہیں۔
مولانا قمر الاسلام (خطیب مرکزی جامع مسجد آگرہ) نے ’’مطلع الاخبار‘‘ کے ایڈیٹر کو کہا کہ فنڈر کا یہ اقرار اخبار میں شائع کروا دو۔
فنڈر: ہاں لکھ لو۔ لیکن تحریف صرف اتنی ہی واقع ہوئی ہے اور اس سے کتب مقدسہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ہاں اختلافِ عبارات کی وجہ سہوِ کاتبین ہے۔
ڈاکٹر: آپ کے بعض نے ڈیڑھ لاکھ اختلافات کا دعوٰی کیا ہے اور بعض نے تیس ہزار کا۔ آپ کس کو مانتے ہیں؟
فرنچ: صحیح یہ ہے کہ چالیس ہزار اختلافات ہیں۔
فنڈر: لیکن اس سے کتب مقدسہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اہلِ انصاف آپ ہی انصاف کریں اور بار بار مفتی ریاض الدین صاحب سے انصاف کا تقاضا کرنے لگا۔
مفتی ریاض الدین: جب ایک وثیقہ میں کچھ حصہ جعلی ثابت ہو گیا ہے تو باقی کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اور جب آپ نے کتب مقدسہ کے بعض مقامات پر تحریف کا اقرار کر لیا ہے تو آپ کی کتاب کو کیسے معتبر مان لیا جائے؟ اس بات کو تبھی حاضرین سمجھتے ہیں۔ مثلاً جج اسمتھ صاحب آپ ہی بتائیے۔ لیکن اسمتھہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مفتی صاحب نے کہا کہ جب دو مختلف عبارتیں پائی جاتی ہیں تو کیا آپ صحیح عبارت کو متعین کر سکتے ہیں؟
فنڈر: نہیں۔
مفتی صاحب: اہلِ اسلام کا دعوٰی بھی یہی ہے کہ یہ مروج مجموعہ کلام سارا کا سارا کلامِ الٰہی نہیں اور آپ نے بھی اس کا اقرار کر لیا ہے۔
فنڈر: مقررہ وقت سے نصف گھنٹہ زائد ہو گیا ہے، باقی بات کل ہو گی۔
مولانا رحمت اللہ: آپ نے سات آٹھ جگہ تحریف کا اقرار کیا ہے۔ کل ہم پچاس ساٹھ مقامات پر ثابت کریں گے انشاء اللہ، لیکن اگر آپ مزید بحث کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین باتیں ہماری ماننا پڑیں گی۔ (۱) ہم آپ سے بعض کتابوں کی سند متصل کا مطالبہ کریں گے وہ آپ کو بیان کرنا ہو گی۔ (۲) جب ہم عیسائی علماء کے اقرار کے ساتھ ۵۰ ۔ ۶۰ مقامات پر تحریف ثابت کریں گے تو یا آپ ان کو تسلیم کریں گے یا تاویل۔ (۳) جب تک آپ دونوں میں سے کوئی بات اختیار نہ کریں آپ ان کتب سے استدلال نہیں کریں گے۔
فنڈر: مجھے منظور ہے لیکن میں بھی آپ سے کل پوچھوں گا کہ محمدؐ کے زمانہ میں کونسی انجیل موجود تھی؟
مولانا: ٹھیک ہے۔
ڈاکٹر صاحب: اگر اجازت دیں تو مولانا ابھی بتا دیں۔
فنڈر: نہیں اب دیر ہو گئی ہے، کل سہی۔
اس پر مناظرہ کا پہلا دن اختتام کو پہنچا۔
مناظرہ کا دوسرا دن
پادری فنڈر کھڑا ہوا اور میزان الحق ہاتھ میں لے کر کچھ قرآنی آیات پڑھنے لگا لیکن عبارات کی بے حد غلطیاں کیں۔
مولانا اسد اللہ (قاضی القضاء): براہِ مہربانی ترجمہ پر اکتفا کریں، عبارات کے بدل جانے سے معانی میں خلل آتا ہے۔
فنڈر: معاف کرنا یہ ہماری زبان کا قصور ہے۔ لکھا ہے: ’’اور کہہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری اور مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال کی جزا ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کی۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں‘‘ (سورۃالشورٰی ۱۵)۔ سورۃ عنکبوت میں ہے ’’اہلِ کتاب کے ساتھ اچھے طریقہ ہی سے مجادلہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور کہو کہ ہم قرآن اور تمہاری جانب آنے والی کتابوں پر ایمان ائ۔ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے تابعدار ہیں‘‘ (آیت ۴۶)۔ سورۃ المائدہ میں ہے ’’آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی جاتی ہیں۔ اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے‘‘ (آیت ۵)۔
پھر فنڈر نے کہا کہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ اہلِ کتاب یہود و نصارٰی کو کہا جاتا ہے اور ان کو جو کتابیں ملی ہیں وہ تورات و انجیل ہیں (سورۃ آل عمران ۳۔۴) تو مذکورہ آیات میں کتاب اور اہلِ کتاب کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تورات و انجیل آنحضرتؐ کے زمانہ میں موجود تھیں اور اہلِ اسلام نے ان کو تسلیم کر کے اپنا ہادی ٹھہرایا اور آنحضرتؐ کے عہد تک ان میں تحریف نہ ہوئی تھی۔
مولانا رحمت اللہ: ان آیات سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام زمان سابق میں نازل ہوا تھا اس پر ایمان لایا جائے اور تورات و انجیل زمانۂ سابقہ میں نازل ہوئی تھیں اور محمدؐ کے عہد میں موجود تھیں۔ لیکن یہ کسی طور سے ثابت نہیں ہوتا کہ زمانۂ محمدؐ تک ان میں تحریف نہ ہوئی تھی۔ جبکہ اللہ تعالٰی نے قرآن کریم میں بیشتر مواقع پر اہلِ کتاب پر تحریف کا الزام لگایا ہے۔ تو جیسے ہم قرآن کی رو سے تورات و انجیل کے کلام اللہ اور منزل من اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح قرآن ہی کی رو سے ان میں تحریف کے وقوع پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اہلِ کتاب کی تصدیق یا تکذیب نہ کرو (صحیح بخاری کتاب التفسیر) کیونکہ ان کی تورات و انجیل محرف ہیں۔
فنڈر: آپ فی الوقت حدیث سے قطع نظر صرف قرآنی آیات پیش کریں۔
مولانا: ان آیات سے یہی دو امور ظاہر ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا اور آپ نے ان کا اقرار بھی میزان الحق میں کیا ہے۔
فنڈر: سورۃ البینہ کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت سے پہلے تحریف نہ کی گئی تھی۔ ’’اہلِ کتاب میں سے کافر لوگ اور مشرکین دلیل آجانے سے قبل باز نہیں آئے، اللہ کا رسول مقدس اور صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اس میں مضبوط کتابیں ہیں اور اہلِ کتاب تفرقہ باز دلیل آنے سے قبل نہ ہوئے‘‘ (آیات ۱۔۴)۔ اور فاضل آل حسن اپنی کتاب ’’الاستفسار‘‘ کے صفحہ ۴۴۸ پر لکھتے ہیں: ’’یعنی جب تک ان کے پاس نبی صلعم نہ آئے تھے اس وقت تک ایک موعود نبی پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس بارے مختلف یا متفرق نہ ہوئے تھے‘‘۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ تحریف و تبدیلی آنحضرت کے بارے میں بشارات کے اندر واقع نہ ہوئی تھی۔
مولانا: ان آیات کا مختار ترجمہ جمہور کے نزدیک یہ ہے جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلویؒ نے کیا ہے ’’نہ تھے اہلِ کتاب میں سے کافر اور مشرکین باز آنے والے (یعنی اپنے مذاہب، بری رسوم، فاسد عقائد سے مثلاً یہودیوں کا انکار نبوت عیسٰی اور عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث وغیرہ) جب تک کہ ان کے پاس دلیل نہ آگئی۔۔۔۔ اور نہ تفرقہ کیا اہلِ کتاب نے (یعنی اپنے ادیان، بری رسوم اور فاسد عقائد میں اس طرح کہ بعض نے ان کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اور بعض بغض و عناد کے باعث قائم رہے) مگر دلیل آجانے کے بعد (یعنی رسول اللہ اور قرآن کے آجانے کے بعد)۔ اور اسی سورۃ کی پہلی آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: ’’حضرت سے پہلے سب دین والے بگڑ گئے تھے۔ ہر ایک اپنی غلطی پر مغرور۔ اب چاہیئے کہ کسی حکیم کے یا ولی یا بادشاہ عادل کے سمجھائے راہ پر آویں سو ممکن نہ تھا جب تک ایسا رسول نہ آوے عظیم القدر ساتھ کتاب اللہ کے اور مدد قوی کے کئی برسمیں ملک ملک ایمان سے بھر گئے‘‘ انتہٰی۔
پس ان آیات کا حاصل یہی ہے کہ اہلِ کتاب اور مشرکین رسول اللہ کے آنے سے پہلے اپنی بری رسوم سے باز نہ آئے تھے اور جس نے آپؐ کے آنے کے بعد مخالفت کی تو اس کی وجہ بغض و عناد ہے۔ لہٰذا آپ کا ان آیات سے مذکورہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے اور فاضل آل حسن کا جواب تنزلی ہے جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں: ’’اگر اس استدلال کی صحت تسلیم کر لی جائے تو صرف یہ ثابت ہو گا کہ ۔۔۔‘‘ یعنی اول تو آپ کا مزعومہ استدلال ہی صحیح نہیں۔ اگر صحیح بھی ہو تو صرف بشاراتِ نبویؐ میں ہی عدمِ تحریف متحقق ہو گی نہ کہ ہر صحیفہ کے ہر موضوع میں۔ علاوہ ازیں فاضل آل حسن نے ساری کتاب میں پکار پکار کر ان کتب کی تحریف کا اعلان کیا ہے۔
فنڈر: اب آپ بتلائیں کہ قرآن میں جس انجیل کا ذکر آیا ہے وہ کونسی انجیل ہے؟
مولانا: کسی ضعیف یا صحیح روایت سے اس کی تعیین ثابت نہیں کہ وہ انجیل متی کی ہے یا یوحنا کی یا کسی اور کی۔ اور ہمیں ان کی تلاوت کا حکم نہیں تھا اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون سی انجیل تھی۔
فنڈر: (مناظرہ میں شریک انگریز حکام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے) یہ سارے اہلِ کتاب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کونسی انجیل تھی۔
ڈاکٹر وزیر خان: قرآن سے صرف یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسٰیؑ پر ایک انجیل نامی کتاب نازل ہوئی تھی اور معلوم نہیں کہ وہ کون سی تھی۔ کیونکہ بہت سی اناجیل اس زمانے میں مشہور تھیں (۶) مثلاً انجیل برنابا اور انجیل برتوکا، واللہ اعلم کہ انجیل سے مراد ان میں سے کون سی انجیل ہے۔ اس زمانہ میں عیسائی فرقہ مانی کیز بھی تھا جو ان مشہور اناجیل کے مجموعہ کو تسلیم نہ کرتا تھا، اور ایک فرقہ یعقوبیہ بھی تھا جو حضرت مریمؑ کو خدا مانتا تھا شاید یہ ان کی انجیل میں لکھا ہو۔ اور قرآن میں کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اعمال کی کتاب خطوط اور مکاشفہ کی کتاب اس انجیل میں داخل تھیں یا نہیں۔
پادری فرنچ: تم ان کتابوں کو جن میں مسیح کے ارشادات درج نہیں ہیں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ لودیسیہ کی کونسل نے مکاشفہ کی کتاب کے علاوہ باقی کتب کو مستند قرار دیا اور انہیں واجب التسلیم کہا اور ہمارے بڑے معتبر علماء مثلاً کلیمنس، انکسدر یانوس، ٹرٹولین، اوریجن وغیرہ نے مکاشفہ کی کتاب کو بھی مستند کہا ہے لیکن ہمارے پاس ان کتب کی سند متصل نہیں ہیں کیونکہ مسیحیت پر بڑے ظلم اور حملے ہوئے اور زیادہ تر یہ مذہب مشکلات میں ہی گھرا رہا۔
ڈاکٹر وزیر خان: یہ کلیمنس کس زمانہ میں تھا؟
فرنچ: دوسری صدی کے آخر میں۔
ڈاکٹر صاحب: کلیمنس نے مکاشفہ کی کتاب سے صرف دو فقرے نقل کیے ہیں لہٰذا صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ کلیمنس نے دوسری صدی کے آخر میں مکاشفہ کی کتاب کو یوحنا رسول کی تصنیف تسلیم کیا، لیکن اس سے پہلے بھی سند متصل نہ تھی اور تواتر لفظی تمام کتاب کا صرف دو فقروں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور باقی علماء ٹرٹولین وغیرہ اس سے بھی بعد کے ہیں، جبکہ اسی زمانہ میں علماء یہ بھی کہتے تھے کہ ’’سرن تھیسن‘‘ جو مشہور ملحد تھا مکاشفہ کی کتاب اس کی تصنیف ہے۔
فرنچ: ایک آدھ کی مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا۔
ڈاکٹر: ہم ایک آدھ کی بات نہیں کرتے بلکہ کئی ایسے نام پیش کر سکتے ہیں جو اس کے مستند ہونے پر شبہ کرتے ہیں مثلاً پوسی بیس مورخ، سرل، یروشلم کی کلیسا اور لودیسیہ کی کونسل اور جیروم کے عہد میں بھی بعض کلیساؤں نے اس کو قبول نہیں کیا (۷)۔
فنڈر: یہ خروج عن المبحث ہے، ہم اس وقت اس انجیل کی بات کر رہے ہیں جو عہد ِ محمدؐ میں موجود تھی۰
مولانا رحمت اللہ: ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہلِ اسلام کا موقف نہیں ہے تو کوئی دلیل پیش کریں ورنہ اسی کو تسلیم کر لیں۔ ہمیں اقرار ہے کہ وحی الٰہی حضرت عیسٰیؑ پر نازل ہوتی تھی لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ انجیل موجودہ عہد جدید ہے اور یہ کہ یہ تحریف سے پاک ہے۔ جبکہ حواریوں کا کلام ہمارے نزدیک قطعاً انجیل نہیں ہے بلکہ انجیل وہ کلام ہے جو حضرت عیسٰیؑ پر نازل ہوا (۸)۔ تخجیل من حرف الانجیل کے مصنف لکھتے ہیں ’’موجودہ اناجیل سچی انجیل نہیں ہیں جو رسولِ خدا کو دی گئی تھیں اور جو منزل من عند اللہ تھی۔‘‘ (باب دوم ص ۲۸)۔ پھر کہتے ہیں ’’اور سچی انجیل وہی ہے جو مسیحؑ نے سنائی‘‘ (ص ۲۹)۔ اور نویں باب میں عیسائیوں کے متعلق لکھتے ہیں ’’ان کو پولس نے اصلی دین سے پُرفریب دھوکہ سے ہٹا دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ ’’لائی لگ‘‘ قسم کے لوگ ہیں اور اس نے تورات کے احکام کو تھپڑ دے مارا‘‘ (ص ۱۲۹)۔ امام قرطبیؒ کتاب ’’الاعلام بما عند النصارٰی من الفساد والاوہام‘‘ باب سوم میں لکھتے ہیں ’’یہ کتاب جو آج کل نصارٰی کے پاس ہے جس کا نام انہوں نے انجیل رکھ چھوڑا ہے وہ انجیل نہیں جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ ’’وانزل التوراۃ والانجیل‘‘ (آل عمران ۳) (ص ۲۰۳)۔ اور اسی طرح اسلاف و اخلاف میں علماء نے تصریحات درج کی ہیں اور پھر کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اقوال مسیح فلانی انجیل میں درج ہیں۔
لہٰذا ہم اس بات کی تعیین نہیں کر سکتے اور اناجیل اربعہ کی حیثیت اخبار آحاد کی سی ہے اور قرن اول کے مسیحیوں سے کوئی معتبر روایت منقول نہیں ہے۔ اس کے متعدد اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس دور میں پوپ (پاپا) کا مکمل تسلط تھا اور انجیل پڑھنے کی عام اجازت نہ تھی لہٰذا بہت کم مسلمانوں نے اس کے نسخے دیکھے کیونکہ عرب کے گرد و نواح میں کیتھولک یا نسطوری فرقہ کے لوگ زیادہ تھے۔
پادری فرنچ: (غم اور غصے سے) تم نے ہماری انجیل پر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ پوپ نے اس میں کچھ بگاڑ نہیں کیا (۹)۔
پادری فنڈر: حضرت عثمانؓ کے احراق قرآن کے قصے کو شد و مد سے بیان کرنے لگا۔
مولانا: آپ کے اعتراضات خارج از بحث ہیں لیکن اگر آپ نے کر ہی دیے ہیں تو جوابات بھی ملاحظہ کریں۔
فنڈر: جب آپ نے انجیل پر اعتراض کیا تو میں نے بھی جواب دیا۔ اب اصل مطلب کی طرف آئیں۔
مولانا: ہم نے شروع ہی سے یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک عہدِ قدیم و عہدِ جدید ایک جیسے ہیں۔ ہم آپ سے ان کی بعض کتابوں کی سند متصل طلب کرتے ہیں۔
فنڈر: صرف انجیل کی بات کریں۔
مولانا: انجیل کی تخصیص لغو ہے، ہم پورے مجموعہ کی۔
فنڈر: خاموش صامت۔
پادری فرنچ نے ایک لمبا طومار نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ’’ہمارے علماء نے اختلاف عبارت تیس یا چالیس ہزار پائے ہیں لیکن یہ ایک نسخہ کی بجائے کثیر نسخہ جات میں ہیں۔ اگر ہم ان اختلافات کو تمام نسخوں پر تقسیم کریں تو ہر نسخہ کے حصہ میں چار سو یا پانچ سو آئیں گے۔ بعض غلطیاں بدعتیوں کے تصرفات سے بھی وقوع پذیر ہوئیں۔ ڈاکٹر کریساخ نے انجیل متی میں ۳۷۰ اغلاط پائیں۔ ۱۷ تو سخت ترین ہیں، ۳۲ اغلاط درمیانی اور باقی ہلکی پھلکی ہیں۔ ہمارے علماء نے ان اغلاط کو زیادہ تر مواضع میں درست کر دیا ہے۔ اور جس کا صرف ایک ہی نسخہ ہو اس کی تصحیح ناممکن ہے اور انجیل کے نسخے بکثرت موجود ہیں تو ان کی تصحیح ممتنع نہیں۔ تصحیح کے قواعد میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:
اول: جب علماء نے دو عبارتوں کو مختلف پایا، ان میں سے ایک فصیح اور دوسری مشکل تھی تو انہوں نے مشکل کو صحیح قرار دیا کیونکہ احتیاط اور عقل و قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شاید فصیح عبارت جعلی ہو۔ دوم: اگر ایک عبارت گرائمر کے لحاظ سے صحیح اور دوسری غلط ہو تو انہوں نے غلط کو صحیح اور صحیح آیت کو جعلی قرار دیا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی ماہر قواعد نے داخل کر دی ہو۔ اور علماء نے ان اغلاط سے واقف کرانے کے بعد کہا کہ ان کے سوا کوئی غلطیاں نہیں ہیں اور اتنی اغلاط سے مقصود اصل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر کنکاٹ کہتا ہے کہ ہم ان محرف عبارات کو داخل رکھیں یا نکال دیں، مسیحی الٰہیات کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔
ڈاکٹر وزیر خان نے جواب دینا چاہا تو پادری فنڈر نے ان کو روک دیا اور جب بھی ڈاکٹر صاحب بولنے لگتے تو فنڈر ان کو روک دیتا۔
مفتی ریاض الدین: یہ ضروری ہے کہ پہلے تحریف کا معنی بیان کیا جائے پھر اس پر بحث کی جائے تاکہ حاضرین کے پلے بھی کچھ پڑے اور وہ صحیح طور سے بحث کو سمجھ سکیں۔
فنڈر نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں بلکہ جو تحریف کا دعوٰی کرتے ہیں وہی اس کا معنی بیان کریں گے۰
مولانا رحمت اللہ: ہمارے نزدیک تحریف کا معنی یہ ہے کہ کلام اللہ میں کمی بیشی یا تبدیلی کی جائے۔ خواہ یہ شرارت اور خباثت سے کی گئی ہو یا اصلاح کی غرض سے۔ اور ہم دعوٰی کرتے ہیں کہ تحریف ان معنوں میں کتب مقدسہ کے اندر واقع ہے۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ہم دلائل دیں گے۔
فنڈر: ہمیں بھی سہو کاتب کا اعتراف ہے (۱۰)۔
مولانا: ہمارے نزدیک سہو کاتب یہ ہے کہ کاتب لام کے بجائے میم اور میم کی بجائے نون لکھ دیتا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک بھی سہو کاتب سے مراد یہی ہے یا یہ کہ تحریف قصدًا، سہوًا، کمی بیشی اور تبدیلی سہوِ کاتب میں شامل ہیں؟ یعنی یہ کہ کاتب حاشیہ کی عبارت متن میں لکھ دیتا ہے یا عمدًا آیات کا اضافہ یا کمی کرتا ہے، یا کوئی چیز تفسیر کے طور پر الحاق کرتا ہے، یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیتا ہے۔
فنڈر: یہ تمام امور ہمارے نزدیک سہو کاتب کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہ قصدًا ہوا ہو یا سہوًا، لا علمی سے یا غلطی سے۔ لیکن آیات میں ایسا سہو صرف پانچ یا چھ مقاموں میں ہے جبکہ الفاظ میں بے شمار۔
مولانا: جب زیادتی، کمی، تبدیلی، قصدًا یا سہوًا آپ کے نزدیک سہوِ کاتب میں شامل ہے اور سہوِ کاتب مقدسہ میں واقع ہے، تو اسی چیز کو ہم تحریف کہتے ہیں۔ پس ہمارے اور تمہارے درمیان صرف لفظی جھگڑا باقی رہ گیا ہے۔ یعنی ہم جس کو تحریف کہتے ہیں اسے آپ سہو کاتب کہتے ہیں۔ تو اختلاف صرف تعبیر میں ہے مسمی و معبر عنہ میں نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چار فقیروں کو ایک درہم دیا۔ ایک رومی تھا، ایک حبشی، ایک ہندی اور ایک عربی۔ انہوں نے اس ایک درہم سے ایک ہی چیز خریدنی تھی جو سب کی پسند کی ہو۔ تو ایک ڈمی نے انگور کا نام اپنی زبان میں لیا۔ حبشی نے انکار کیا اور اپنی زبان میں کہا میں تو انگور ہی کھاؤں گا۔ تو ان چاروں میں نزاع لفظی ہے، مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ اسی طرح تحریف اور سہو کاتب کا مسئلہ ہے۔ پھر مولانا نے بلند آواز سے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے اور پادری صاحب کے درمیان جھگڑا صرف لفظی ہے کیونکہ ہم جس تحریف کا دعوٰی کرتے ہیں پادری صاحب نے اسے قبول کر لیا ہے لیکن وہ اسے سہوِ کاتب کہتے ہیں۔
فنڈر: اس قسم کے سہو سے متن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔
مولانا اسد اللہ صاحب (حیرانی سے): متن کیا چیز ہے؟
فنڈر
(ناراض ہو کر): میں نے کئی دفعہ بتایا ہے اب کتنی بات بتاؤں؟ متن سے ہماری
مراد الوہیت مسیح، تثلیث، کفارہ شافع اور یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں۔
مولانا
رحمت اللہ: تفسیر ہنری واسکاٹ میں بھی یہی لکھا ہے کہ مقصود اصلی میں کچھ
بھی فرق ان اغلاط سے نہیں پڑا۔ لیکن ہم نہیں سمجھ سکے کہ جب تحریف ثابت ہو
گئی ہے تو کیا دلیل ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں آیا۔ اور جب تحریف ہر قسم کی
واقع ہوئی ہے تو کیا دلیل ہے کہ وہ نو دس آیات جن میں تثلیث کا ذکر ہے وہ
تحریف سے محفوظ ہیں؟
فنڈر: متن کی
تحریف تب ثابت ہو گی کہ تم کوئی قدیم نسخہ دیکھو، اس میں الوہیت مسیح کا
ذکر نہ ہو اور موجودہ نسخہ میں ہو، اور اس میں کفارہ مسیح کا تذکرہ نہ ہو
اور موجودہ نسخہ میں ہو۔
مولانا:
ہمارے ذمہ صرف یہ تھا کہ ہم اس مروجہ مجموعہ کا مشکوک ہونا ثابت کریں اور
وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب آپ کی کتاب مشکوک ہے۔ ہاں آپ کا دعوٰی ہے کہ بعض
مواضع تحریف سے پاک ہیں اور بعض محرف ہیں۔ تو یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان بعض
مواضع کی سلامتی اور صحت کو ثابت کریں۔ اب صرف ایک بات رہ گئی ہے جو جواب
طلب ہے۔ وہ یہ کہ یہ سہوِ کاتب جو آپ کے ہاں مسلّم ہیں، کیا تمام نسخوں میں
ہے؟
فنڈر: ہاں یہ سہو تمام نسخوں میں پایا جاتا ہے۔
اس پر پادری فرنچ نے اعتراض کیا تو فنڈر نے کہا کہ پادری فرنچ کی رائے بہتر ہے۔ قاضی القضاۃ مولوی محمد اسد اللہ نے کہا کہ آپ پہلے اعتراف کر چکے ہیں۔ فنڈر نے کہا، میں نے غلطی کی اور میں نے یقین سے نہیں کہا، شاید کہ ایک سہو عبرانی متن میں ہو اور یونانی میں نہ ہو۔
مولانا رحمت اللہ: اگر ہم بعض ایسے مقامات دکھلا دیں جہاں پر آپ کے مفسروں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جملہ پہلے زمانہ میں ایسا تھا لیکن اب تمہارے معتبر عبرانی متن میں ویسا نہیں ہے تو تم کیا کہو گے؟
فنڈر: اس سے متن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔
ڈاکٹر وزیر خان: لا شک لا ریب مقصودِ اصلی میں خلل آئے گا کیونکہ جب اختلافات عبارات بہت ہیں، مثلاً ہم فرض کرتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی کی کتاب ’’گلستان سعدی‘‘ کے مختلف نسخوں میں ایک مقام پر مختلف عبارات پائی جاتی ہیں، اس صورت میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ سعدی کی اصل عبارت کون سی ہے۔ پس جب سینکڑوں نسخہ جات میں اختلاف ہے اور کسی کو کسی دوسرے پر ترجیح نہیں ہے تو مقصودِ اصل میں تغیر کا امکان ہے۔ اور ہمارے نزدیک انجیل، مسیحؑ کے اقوال منزل من اللہ سے عبارت ہے اور وہ مشتبہ ہو چکی ہیں۔
فنڈر: مجھے مختصر جواب دیں کہ آپ متن کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو مناظرہ آئندہ ہفتہ کو ہو گا کیونکہ ہم باقی مسائل میں اس کتاب (انجیل) سے استدلال کریں گے۔ ہمارے نزدیک عقل کتاب کی محکوم ہے نہ کہ کتاب عقل کی۔
مولانا رحمت اللہ: جب آپ کے اعتراف کے مطابق کتب میں تحریف ثابت ہو گئی تو بایں سبب یہ ہمارے نزدیک مشتبہ ہو گئیں۔ ہم نہیں مانتے کہ غلطیاں متن میں نہیں ہوئیں۔ آپ کو روا نہیں ہے کہ آپ ہم پر اس کتاب سے مناظرہ کے باقی مسائل میں استدلال کریں کیونکہ یہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہیں۔
فرنچ: تم نے یہ تحریفات و اغلاط ہماری تفاسیر سے نکالی ہیں گویا یہ مفسرین تمہارے نزدیک معتبر ہیں۔ تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے علاوہ اور مقامات میں غلطیاں نہیں ہیں۔
مولانا: ہم نے ان علماء کے اقوال الزاماً نقل کیے ہیں، ان کو معتبر مانتے ہوئے نہیں۔ اور پادری فنڈر نے اپنی کتاب میں بیضاوی اور زمحشری کے کچھ اقتباسات نقل کیے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہیں۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں؟
فنڈر: نہیں۔
مولانا: اسی طرح ہم بھی تمہارے مفسروں کی ساری باتیں نہیں مانتے۔
فنڈر: مجھے مختصر جواب دیں، ہاں یا نہیں میں۔
مولانا: نہیں! کیونکہ وہ متن جو آپ کے نزدیک مقصود اصل سے عبارت ہے وہ ہمارے نزدیک تحریف کے سبب سے مشتبہ ہو گیا۔ اور تم نے پہلے دن سات یا آٹھ جگہ تحریف اور چالیس ہزار اختلافاتِ عبارات کا اقرار کیا ہے جس کو آپ سہوِ کاتب کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور اسے ہم تحریف کہتے ہیں۔ اور ہمارا مقصود صرف یہی تھا کہ یہ مجموعہ مشکوک ثابت ہو جائے اور یہ بفضل اللہ تعالٰی ہو چکا ہے۔ متن کی عدمِ تحریف کا اثبات آپ پر لازم ہے۔ ہم تو دو ماہ تک بلا عذر حاضر ہیں مگر یہ ہے کہ یہ مجموعہ ہم پر حجت نہ ہو گا اور ان سے منقول دلیل ہم پر لازم نہ ہو گی۔ البتہ اگر تمہارے پاس باقی مسائل بارے کوئی دلیل ہو تو پیش کرو۔
اس کے ساتھ ہی مناظرہ کا دوسرا اور آخری دن اختتام کو پہنچ گیا۔
حواشی
(۱) پادری جے پیٹرسن اسمتھ لکھتے ہیں: ’’وہ (پولوس) یہ کہتا ہے کہ
شریعت صرف ایک محدود وقت کے لیے تھی اس کا کام محض لوگوں کو مسیح کی
بادشاہت کے لیے تیار کرنا تھا‘‘۔ (حیات و خطوط پولس مطبوعہ ۱۹۵۲ء ص ۸۲۔۸۳))
(۲) عصرِ حاضر کے ایک عیسائی مصنف کے قلم سے اس کا اعتراف ملاحظہ فرمائیے: ’’جوں جوں زمانہ گزرتا گیا پرانے عہد نامہ کی پیشین گوئیوں کا مجموعہ بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے مسیح پر اطلاق میں تجاوز ہو گیا۔ ’’یوسطین شہید کا طریفو یہودی سے مکالمہ‘‘ اور ’’یہودیوں کے خلاف شہادت‘‘ اس قسم کے تجاویز کی مثالیں ہیں۔ جب کلیسا میں زیادہ تر یونانی زبان بولنے والے شریک ہونے لگے تو یہ شہادتیں ترجمہ ہفتادہ پر مبنی تھیں اور بعض اوقات یہ ترجمہ عبرانی سے نہیں ملتا تھا۔ وہ یہودی جن کی طرف ان شہادتوں کا اشارہ تھا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ ’’یہ ترجمہ عبرانی سے بڑا ہی مختلف ہے‘‘ (طریفو نے یوسطین کو یہی کہا تھا) لیکن یونانی مسیحی یہ کہا کرتے تھے کہ ’’وہ پیشین گوئیاں جو مسیح کی آمد کے بارے میں ہیں ان میں یہودیوں نے دیدہ و دانستہ رد و بدل کر دیا ہے‘‘ (طلوع مسیحیت۔ مصنفہ ایف ایف بروس ایم اے ڈی ڈی ۔ مترجمہ اے ڈی خلیل بی اے بی ٹی ۔ مطبوعہ ۱۹۸۶ء ص ۸۱۔۸۲ ۔ شائع کردہ مسیحی اشاعت خانہ لاہور)
(۳) پادری طالب الدین لکھتے ہیں ’’وہ (یہودی) یسوع کو گنہگار سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کی ان رسومات سے اتفاق نہیں کرتا تھا جو انہوں نے اور ان کے آبا و اجداد نے کلامِ الٰہی پر اضافہ کر دی تھیں‘‘ (حیات المسیح مطبوعہ ۱۹۴۴ء ص ۱۵۴)۔ ایک دوسرے عیسائی عالم کے مطابق ’’مسیح اور اس کے شاگرد برابر طور پر یہودیوں کو کتبِ مقدسہ میں تحریف کے ملزم گردانتے تھے‘‘۔ (التوراۃ تاریخھا و غایاتھا ۔ ترجمہ سہیل میخائل دیب۔ طبع سادس ۱۹۸۲ء مطبوعہ بیروت ص ۷۸)
(۴) پادری جی ٹی مینلی لکھتے ہیں ’’مصنف کے بارے میں اول یہ بات جاننی ضروری ہے کہ آیا یہ کتاب حقیقی واقعات پیش کرتا ہے یا ڈرامہ ہے یا کچھ ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ حقیقت اور تمثیل (ڈرامہ) کے بیچوں بیچ ہے۔ قدیم روایت میں اسے تاریخی کتاب تسلیم کیا گیا ہے۔‘‘ (ہماری کتب مقدسہ ۔ مطبوعہ ۱۹۸۷ء ص ۲۵۹)۔ پادری مینلی نے صرف ایک نظریہ کا ذکر کر کے اس کے حق میں شہادتیں پیش کی ہیں۔
(۵) ان آیات کو کریب، شولز، آدم کلارک، آگسٹائن اور ہورن نے الحاقی قرار دیا ہے یعنی یہ بعد میں داخل کی گئیں۔ تفصیلات اظہار الحق ج ۱ ص ۲۵۷ اور فنڈر نے اگلی سطر میں اعتراف کیا ہے۔
(۶) مسیحی مجلہ سہ ماہی ’’ہما‘‘ لکھنؤ (انڈیا) میں لکھا ہے ’’بے شک یہ صحیح ہے کہ مختلف اشخاص نے جعلی انجیلیں تحریر کر کے ان کے فروغ کی کوشش کی اور مسیحیت کے ابتدائی دور میں کئی انجیلیں وجود میں آگئیں۔‘‘ (اکتوبر دسمبر ۱۹۶۷ء ص ۴ کالم ۱ و ۲)۔ ان میں سے کم از کم ایک جعلی انجیل آنحضرتؐ کے عہد میں موجود تھی۔ (رسالہ تحریف انجیل و صحت انجیل از پادری ڈبلیو میچن ص ۵)
(۷) بشپ ولیم جی ینگ نے تاریخ کلیسا کی تازہ ترین تصنیف ’’رسولوں کے نقشِ قدم پر‘‘ کے صفحہ ۲۰۰ پر مستند اور زیربحث کتب کے بارے میں ایک نقشہ درج کیا ہے جس کے مطابق ’’جنوبی ہند کی سریانی کلیسا‘‘ مکاشفہ کی کتاب کو غیر مستند قرار دیتی ہے۔ یوسی بیس مورخ اور نصیین کی درسگاہ کے ہاں یہ کتاب زیربحث ہے۔ چار مزید مآخذ اس کے بارے میں خاموش ہیں یعنی اس کو غیر مستند قرار دیتے ہیں۔ پادری ایچ والر صاحب لکھتے ہیں کہ ’’اس کتاب کو رسولی تصنیف ماننے میں کچھ چیزیں درکار ہیں لہٰذا بعض مصنفین نے اس کتاب کے رسولی تصنیف ہونے پر شکوک ظاہر کیے‘‘۔ (تفسیر مکاشفہ مطبوعہ ۱۹۵۸ء ص ۷)۔ ’’کتاب کا پس منظر غیر یقینی ہے‘‘ (انجیل مقدس کا مطالعہ از فادر کارلسٹن ۔ مطبوعہ ۱۹۶۷ء ص ۱۳۶)
(۸) عیسائیوں کے موجودہ نظریہ الہام کے مطابق عیسٰیؑ پر کوئی خارجی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ انجیل کا لفظ ان کی آمد کی بشارت اور خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سیالکوٹ کے پادری برکت اے خان نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ ’’اصول تنزیل الکتاب‘‘ کے نام سے تصنیف کیا ہے۔
(۹) پادری لوئیس برک ہاف لکھتے ہیں: ’’رومن کیتھولک کلیسیا کی تعلیم یہ تھی کہ کتاب مقدس کا بذاتِ خود کوئی اختیار نہیں کیونکہ اس کا وجود کلیسیا کی طرف سے ہے‘‘ ۔۔۔۔ گو رومن کیتھولک کلیسیا پاک نوشتوں کی اہمیت اور افادیت کو مان لیتی ہے تاہم وہ اس کو قطعی ضروری نہیں سمجھتی۔ اس کلیسیا کی دانست میں یہ کہنا کہ پاک نوشتوں کو کلیسا کی ضرورت ہے، زیادہ صحیح ہے، بہ نسبت اس کے کہ کلیسا کو پاک نوشتوں کی ضرورت ہے‘‘ (مسیحی علم الٰہی کی تعلیم۔ مطبوعہ ۱۹۸۷ء ص ۷۲ و ۷۳)۔ قارئین خود فیصلہ کر لیں کہ اس صورتحال میں پوپ نے پاک نوشتوں کو کیا خاک اہمیت دی ہو گی۔
(۱۰) سہوِ کاتب اور کتبِ مقدسہ میں اغلاط کی اقسام کے لیے آرچ ڈیکن برکت اللہ کی تصنیفات ’’صحت کتب مقدسہ‘‘ حصہ دوم باب اول اور ’’قدامت و اصلیت انجیل اربعہ‘‘ جلد دوم ص ۲۳۹ ملاحظہ فرمائیں۔
’’جمہوریت‘‘ — ماہنامہ الفجر کا فکر انگیز اداریہ
ادارہ
ہر قوم اور ہر ملت کے اپنے مخصوص نظریات ہوتے ہیں۔ ان نظریات کی بنا پر ان کا اپنا سیاسی نظام وضع ہوتا ہے۔ پھر اس نظام کو چلانے کے لیے اداروں کی تشکیل کی جاتی ہے۔ امت مسلمہ کے سوا جتنی بھی اقوام اور نسلی گروہ دنیا میں موجود ہیں انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی گزارنے کے ضابطے اور اصول خود وضع کیے ہیں۔ ان کے مطابق دساتیر بنائے گئے ہیں۔ ان پر وہ عمل پیرا ہیں۔ وہ اپنے اصولوں اور ضابطوں میں ترمیم و اضافہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر زیادہ تر اپنی زندگی کا ایسا لائحہ عمل اپناتے ہیں جس کے ذریعے وہ زندگی کے عیش و آرام کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں اور ہوائے نفس کی بہتر تسکین کریں۔ چونکہ بہت ساری اقوامِ عالم نے مذہب اور روحانیت کو خیرباد کر دیا ہے یا کم از کم ان کی اجتماعی زندگی میں مذہب کی مداخلت ممنوع ہو چکی ہے اس لیے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دوسرے اجتماعی دائروں میں وہ عام انسانوں کے افکار، خیالات اور نت نئے بدلتے ہوئے نظریات کے مطابق اپنا لائحہ عمل بناتے رہتے ہیں۔ وہی ان کا دین اور وہی ان کا نظریۂ حیات ہے۔
مغربی اقوام نے بڑے تجربوں کے بعد ایک سیاسی نظام وضع کیا ہے۔ اس نظام کے لیے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں جدوجہد کی، قربانیاں دیں، اپنے مذہبی پادریوں سے لڑائیاں لڑیں، رائے عامہ کو تبدیل کیا، نئی فکر اور نئے زاویے تجویز کیے۔ تاآنکہ مذہب اور مذہبی شخصیات کو ریاست کے معاملات سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا۔ ریاست اور مذہب کی جدائی کا نظریہ مغربی طرزِ فکر کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد خدا اور مذہب کا معاملہ کائنات کے اجتماعی امور سے کٹ جاتا ہے۔ یہ انسان کے اجتماعی معاملات سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان خودمختار، مالک الملک، اور حاکمیتِ اعلٰی کا مظہر سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو اس کائنات کی سُپر قوت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تصور اور فلسفہ ہے ’’جمہوریت‘‘ کا جسے ایک سیاسی نظام کے طور پر مغربی اقوام نے وضع کر کے اپنایا ہے۔
’’جمہوریت‘‘ آنے کے بعد چرچ کی حاکمیت ختم ہو گئی، اب چرچ فقط چند مقدس مجسموں کے رکھنے کی جگہ قرار پائی۔ چرچ کی زیارت کرنا، مجسموں کے سامنے سر جھکانا، کچھ دعائیں اور گیت پڑھنا، نذر و نیاز دینا، پوپ پال کی بہتر خدمت کرنا اور دیگر اس قسم کی فضول اور لا یعنی رسومات کا بجا لانا مذہب اور روحانیت ٹھہرا۔ جمہوریت میں چونکہ رائے عامہ کی مرضی پر قوانین بنتے اور بدلتے ہیں، ان کی آراء پر حکومت قائم ہوتی اور ختم ہوتی ہے، اس لیے رائے عامہ کی تنظیم کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود لازمی قرار پایا۔ گویا سیاسی جماعتوں نے مذہب کی جگہ لے لی۔ پہلے معاشرہ کی تنظیم مذہب کرتا تھا اب اس کی جگہ سیاسی پارٹی نے لے لی۔ سیاسی پارٹیوں کی اس اہمیت نے معاشرے کے متمول اور دولتمند طبقے کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ پارٹیوں پر اپنا تسلط قائم کریں۔ یوں سیاسی پارٹیاں جاگیردار، سرمایہ دار، اور مالدار افراد کی لونڈیاں بن گئیں۔ یہ لوگ ان کے ذریعے رائے عامہ پر اثرانداز ہوتے رہے، ان کو اپنے حق میں استعمال کرتے رہے۔ نفسیاتی حربوں اور پروپیگنڈہ کے وسیع ہتھکنڈوں کے ذریعے عوام کا استحصال کیا جاتا رہا اور اس کا نام ’’جمہوریت‘‘ تجویز کیا گیا۔
مذہب اور سیاست کی جدائی کے اس فلسفہ سے کمیونزم نے بھی جنم لیا۔ کمیونزم درحقیقت مغربی فکر و فلسفہ کی دوسری شاخ کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے معاشی نظریہ میں بزعم خود یہ ترقی پسندانہ تصور دیا کہ پیدواری وسائل انفرادی ہاتھوں کے بجائے ریاست کے ہاتھوں میں ہونے چاہئیں تاکہ کوئی فرد کسی فرد کا استحصال نہ کر سکے۔ مگر انہوں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اگر ریاست کے افراد (کمیونسٹ پارٹی) جن کے ہاتھوں میں پیداواری ذرائع ہوں گے اگر وہی استحصال کرنے لگیں تو ان کا احتساب کون کرے گا؟
چنانچہ مغربی فکر و فلسفہ کے زیرسایہ وضع کردہ یہ دونوں معاشی نظام، سرمایہ داری اور کمیونزم، آج عالمِ انسانیت کا پہلے سے زیادہ استحصال کر رہے ہیں۔ آج کا انسان ان دونوں نظاموں کے مظالم سے شدید اذیت میں مبتلا ہے۔
اُمتِ مُسلمہ آج مغربی اور مشرقی اقوام کے مقابلے میں اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس محفوظ شکل میں ’’خدائی ضابطۂ حیات‘‘ موجود ہے۔ اس کے ہاں اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، جو انسان کی انفرادی زندگی اور ریاستی امور سے متعلق ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ نبوت کے معیار کے مطابق خلفاء راشدینؓ کی طرزِ حکومت کا نمونہ تقلید کے لیے دستیاب ہے۔ ایسے عظیم الشان دستورِ حیات اور قابلِ عمل تعلیمات کے ہوتے ہوئے یہ امت ہرگز اس بات کی محتاج نہیں کہ وہ اِدھر اُدھر نظر دوڑائے، دوسری اقوام کی طرف دیکھے، ان کے نظریات سے متاثر اور مرعوب ہو، ان کی تقلید کرنے پر اتر آئے۔ مگر اس کو بدنصیبی یا بدبختی ہی کہا جائے کہ آج یہ امت مسلمہ بھی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی دائروں میں اقوامِ غیر کی نقالی کرنے پر چل پڑی ہے۔ وہ اپنے دینِ برحق اور اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں ان سیاسی اور معاشی نظاموں پر جان چھڑکتی ہے جو ان کے نظریات اور ایمان کے عین ضد ہیں۔
اسی جمہوریت کو ہی لے لیجئے کہ یہ سیاسی نظام مذہب اور سیاست کی جدائی پر منتج ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں سیاست مذہب کا جزو لاینفک ہے۔ اسلام میں حاکمیتِ اعلٰی عوام کی بجائے خدا کو حاصل ہے اور سپر قوت عوام نہیں بلکہ ذاتِ ذوالجلال والاکرام ہے۔ قوانین سازی عوام کی مرضی پر نہیں خدا اور رسول کے ضابطوں کے مطابق ہوتی ہے۔ حکومت سازی میں عوام کی آراء کو گِنا نہیں، تولا جاتا ہے۔ جن کے لیے زیادہ ہاتھ کھڑے ہو گئے ان کو نہیں بلکہ اہل رائے کی تائید سے متقی اور باصلاحیت قیادت کو آگے لایا جاتا ہے۔ یہاں شخصی آمریت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی بلکہ نظریہ کی حکمرانی ہوتی ہے۔ سربراہِ مملکت کے لیے بھی نظریہ کی اطاعت کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکومتی عہدیداروں کو عدالت کے سامنے عام انسانوں کے برابر سمجھا گیا ہے۔ سربراہ کو رعایا میں سے ایک عام آدمی بلاک روک ٹوک احتساب کر سکتا ہے۔ اس عام آدمی کے اطمینان کے بعد ہی وہ حکومت کرنے کا اہل سمجھا جائے گا۔
اسلام میں انسانوں کی آزادی کا وہ تصور نہیں جیسا کہ مغرب میں دیا جاتا ہے جو کہ دراصل انسانوں کی آزادی ہیں بلکہ ان کا استحصال ہے۔ اسلام میں کسی فرد یا کسی اجتماع کی غلامی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلامی نظامِ سیاست میں انسان کو فقط خداوند قدوس کا عبد قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا بندہ نہیں ہے۔ حکومتی سربراہ کو عام زندگی میں کچھ بھی امتیازی اختیارات حاصل نہیں، وہ بھی عام رعایا کی طرح قانون میں برابر ہے اور اس کو عام انسانوں کی طرح اپنے شب و روز بسر کرنے چاہئیں۔ وہ اگر ریاستی وسائل سے کچھ زیادہ اختیارات استعمال کرتا ہے یا اپنی ذاتی زندگی کا معیار عام رعایا سے زیادہ رکھتا ہے تو وہ عادل سربراہ نہیں ہو گا اور عام مسلمان اس کو معزول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
ان حقائق کے پیشِ نظر اسلام کا اپنا ایک مستقل سیاسی نظام ہے جس کو نہ جمہوریت کہا جائے گا نہ اس پر اسلامی جمہوریت جیسی لغو اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ اسلام کے معاشی تصورات پر سوشلزم کا اطلاق یا ان کو اسلامی سوشلزم سے تعبیر کرنا بھی جہالت اور منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ عالمِ اسلام ایک طویل عرصہ سے اپنے سیاسی اور معاشی نظریات کو بھول چکا ہے۔ وہ بادشاہوں، آمروں اور ڈکٹیٹروں کو خلفاء کے نام سے پکارتا رہا اور تاریخ میں اسے اسی طرح یاد کرتا رہا۔ وسائلِ رزق پر حکمران خاندانوں کا تسلط رہا، وہی لوگ جاگیردار اور سرمایہ دار بنتے گئے اور ہم نے ذاتی ملکیت کے نام پر ان کو تحفظ دیا۔ اب یہ بات اسلام کے سر تھوپی جا رہی ہے کہ اسلام میں مطلق العنان حکمرانوں کا جواز بھی ہے اور اسلام جاگیرداروں کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ مگر معاملہ قطعی طور پر اس کے برعکس ہے۔ اسلام کا معاشی اور سیاسی سسٹم فقط وہی ہے جو اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور جس کا عملی نمونہ خلفاء راشدینؓ کے دورِ حکومت میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، فاطمیہ، سلجوقیہ، صفوی، عثمانی، غزنوی، غوری، مغل وغیرہ وغیرہ حکمرانوں کے ادوار میں جو کچھ ہوا وہ (سب کا سب) ہرگز اسلام نہیں ہے اور نہ ہی اسلام اس (سب) کا ذمہ دار ہے۔ یہ ’’مسلم‘‘ حکمرانوں کی عیاشیوں، بدمستیوں، فضول خرچیوں، اقتدار کی ہوس کے لیے قتل و غارت گری اور جنگ و جدل کا دور ہے، یہ پوری تاریخ حقیقی اسلام سے انحراف کی تاریخ ہے، الّا ما شاء اللہ۔
امت مسلمہ کالونیز دور سے گزر کر اب ایک نئے دور کا آغاز کر چکی ہے۔ اب اس دنیا میں نظریات کی جنگ ہے، دنیا نظریات کے تغلب سے فتوحات کرتی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے فطری نظریہ ’’اسلام‘‘ کی طرف پورے شعور اور استقامت کے ساتھ آنا ہو گا۔ اس نظریہ کے ساتھ کامل وابستگی اختیار کرنی ہو گی۔ اس کے ساتھ اقوامِ غیر کے مسلط شدہ سیاسی نظاموں سے نجات حاصل کرنی ہو گی۔ مغرب کی سیاست، مغرب کی ثقافت اور مغرب کے فکر و فلسفہ کو مسترد کرنا ہو گا۔ کفر کے سیاسی غلبہ سے نجات کی یہی راہ ہے کہ ہمیں کفر کی سیاست اپنانے کی بجائے کفر کی سیاست سے برأۃ کا اعلان کرنا ہو گا۔ اب ہمیں کھل کر یہ کہنا ہو گا اور یہ بات ایمان کی علامت میں شمار ہو گی کہ ہم جمہوریت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم سرمایہ دارانہ معاشی نظام کو انسانیت کے لیے قاتل نظام تصور کرتے ہیں۔ ہم کمیونزم کو انسانی شرف و عزت کی توہین سمجھتے ہیں، ہم آمریت اور ڈکٹیٹرشپ سے کلی طور پر بیزار ہیں۔
ہمارے دینی مدارس — مقاصد، جدوجہد اور نتائج
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
(ہمارے معاشرہ میں دینی مدارس کا کردار تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے اور ان اداروں نے بے سروسامانی اور مسلسل حوصلہ شکنی کے باوجود اپنے کردار کو جس استقامت و حوصلہ کے ساتھ نبھایا ہے وہ ملتِ اسلامیہ کی تاریخ کا ایک تابناک باب ہے۔ مگر کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جن کے حوالے سے دینی مدارس کا کردار تشنہ ہے اور وقت کے تقاضوں اور اہلِ نظر کی توقعات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تصویر کے دونوں رخ سامنے لائے جائیں اور حقائق کا بے لاگ تجزیہ کیا جائے۔ زیرِنظر مضمون میں تصویر کے روشن پہلو کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کی گئی ہے۔ تصویر کے دوسرے رخ پر مدیر الشریعہ کا تجزیاتی مضمون آئندہ شمارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ ادارہ)
دینی مدارس کے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ملک بھر کے دینی مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سالانہ تعطیلات گزارنے کے بعد اپنے تعلیمی سفر کے نئے مرحلہ کا آغاز ماہِ گزشتہ کے وسط میں کر چکے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان ہزاروں دینی مدارس کا تعلق مختلف مذہبی مکاتبِ فکر سے ہے اور ہر مذہبی مکتب فکر کے دینی ادارے اپنے اپنے مذہبی گروہ کے تشخص و امتیاز کا پرچم اٹھائے نئی نسل کے ایک معتد بہ حصہ کو اپنے نظریاتی حصار اور فقہی دائروں میں جکڑنے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہیں۔
دینی مدارس کے موجودہ نظام کی بنیاد امدادِ باہمی اور عوامی تعاون کے ایک مسلسل عمل پر ہے جس کا آغاز ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد اس جذبہ کے ساتھ ہوا تھا کہ اس معرکۂ حریت کو مکمل طور پر کچل کر فتح کی سرمستی سے دوچار ہوجانے والی فرنگی حکومت سیاسی، ثقافتی، نظریاتی اور تعلیمی محاذوں پر جو یلغار کرنے والی ہے اس سے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ اور تہذیب و تعلیم کو بچانے کی کوئی اجتماعی صورت نکالی جائے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے دیوبند میں مدرسہ عربیہ (دارالعلوم دیوبند)، سہارنپور میں مظاہر العلوم اور مراد آباد میں مدرسہ شاہی کا آغاز ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور افغانستان کے طول و عرض میں ان مدارس کا جال بچھ گیا۔ ان مدارس کے لیے بنیادی اصول کے طور پر یہ بات طے کر لی گئی کہ ان کا نظام کسی قسم کی سرکاری یا نیم سرکاری امداد کے بغیر عام مسلمانوں کے چندہ کی بنیاد پر چلایا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انتہائی سادگی اور قناعت کے ساتھ ان مدارس نے برصغیر کے مسلمانوں کی بے پناہ دینی و علمی خدمات سرانجام دیں۔
ان مدارس کے منتظمین اور اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ایسے مردانِ باصفا کی تھی جو وقت کی رفتار کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیتے تو دنیاوی زندگی کی سہولتیں اور آسائشیں بے دام غلام کی طرح ان کے دروازے پر قطار باندھے کھڑی نظر آتیں، لیکن غیور و جسور فقراء کے اس گروہ نے مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے عظیم مشن کی خاطر نہ صرف ان آسائشوں اور سہولتوں کو تج دیا بلکہ اپنی ذاتی انا اور عزتِ نفس کی قیمت پر صدقات، زکوٰۃ و عشر اور ایک ایک دروازے سے ایک ایک روٹی مانگنے کے لیے اپنی ہتھیلیاں اور جھولیاں قوم کے سامنے پھیلا دیں۔ اور ہر قسم کے طعن و تشنیع اور تمسخر و استہزاء کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے انتہائی صبر و ثبات کے ساتھ ایک ایسے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی جس نے برصغیر میں اسپین کی تاریخ دہرانے کی فرنگی خواہش اور سازش کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ اور برطانوی حکمران بالآخر یہی حسرت دل میں لیے ۱۹۴۷ء میں یہاں سے بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور ہوگئے۔
دینی مدارس کی جدوجہد کے نتائج و ثمرات کے حوالہ سے اگر معاشرے میں ان مدارس کے اجتماعی کردار کا تجزیہ کیا جائے تو تمام تر خامیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کی شکل کچھ اس طرح سامنے آتی ہے کہ:
- لارڈ میکالے نے مسلمانوں کی نئی نسل کو ذہنی لحاظ سے انگریز کا غلام بنانے اور نوآبادیاتی فرنگی نظام کے کل پرزوں کی شکل میں ڈھالنے کے لیے جس نظامِ تعلیم کی بنیاد رکھی تھی اس کے مقابلے میں دینی مدارس ایک مستحکم اور ناقابل شکست متوازی نظام تعلیم کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اور اس طرح فرنگی تعلیم و ثقافت سے محفوظ رہنے کی خواہش رکھنے والے غیور مسلمانوں کو ایک مضبوط نظریاتی اور تہذیبی حصار میسر آگیا۔
- جدید عقل پرستی کی بنیاد پر دینی عقائد و روایات سے انحراف، انکارِ ختم نبوت، انکارِ حدیث اور اس قسم کے دیگر اعتقادی اور مذہبی فتنوں نے سر اٹھایا تو یہ دینی مدارس پوری قوت کے ساتھ ان کے سامنے صف آراء ہوگئے اور ملت اسلامیہ کی راسخ الاعتقادی کا تحفظ کیا۔
- فرنگی تہذیب اور یورپی ثقافت کی طوفانی یلغار کا سامنا کرتے ہوئے دینی مسلم ثقافت کو ایک حد تک بچانے اور بطور نمونہ باقی رکھنے میں ان مدارس نے کامیابی حاصل کی۔
- قرآن و سنت کے علوم، عربی زبان اور دینی لٹریچر کو نہ صرف زمانہ کی دستبرد سے بچا کر رکھا بلکہ ملک میں ان علوم کے حاملین اور مستفیدین کی ایک بڑی تعداد پیدا کر کے اگلی نسلوں تک انہیں من و عن پہنچانے کا اہتمام کیا۔
- دینی مدارس کے اس نظام نے تحریک آزادی کو شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ، مولانا عبید اللہ سندھیؒ، مولانا حسین احمدؒ مدنی، مولانا ابوالکلام آزادؒ، مولانا حبیب الرحمان لدھیانویؒ، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ، مولانا عبد الرحیم پوپلزئیؒ، مولانا تاج محمودؒ امروٹی، مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوریؒ، مولانا سید محمد داؤد غزنویؒ، مولانا عبد القادر قصوریؒ اور صاحبزادہ سید فیض الحسن، جبکہ تحریک پاکستان کو علامہ شبیر احمدؒ عثمانی، مولانا ظفر احمدؒ عثمانی، مولانا اطہر علیؒ، مولانا عبد الحامدؒ بدایونی، اور مولانا محمد ابراہیمؒ سیالکوٹی جیسے بے باک، مخلص اور جری راہنماؤں کی صورت میں ایک مضبوط نظریاتی قیادت مہیا کی جن کے ایثار، قربانی اور جدوجہد نے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کیا۔
- اور اب افغانستان کی سنگلاخ وادیوں میں کمیونزم کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا جائزہ لے لیا جائے جس نے روسی افواج کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کرنے کے علاوہ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں میں دینی بیداری کی لہر دوڑا دی ہے اور روسی استعمار کے آہنی پنجے کو ڈھیلا کر کے مشرقی یورپ پر کمیونزم کی گرفت کو کمزور کر دیا ہے۔ افغانستان کے غیور مسلمانوں کے اس عظیم جہاد کی قیادت کا ایک بڑا اور فیصلہ کن حصہ انہی دینی مدارس کا تربیت یافتہ ہے۔ اور اس طرح افغانستان کو روسی کمیونزم کے لیے ’’پانی پت‘‘ کا میدان بنا دینے کا کریڈٹ دینی مدارس کے اسی نظام کے حصہ میں آتا ہے۔
الغرض دینی مدارس کی یہ عظیم جدوجہد اور اس کے نتائج و ثمرات تاریخ کے صفحات پر اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ کوئی ذی شعور اور منصف مزاج شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فرنگی اقتدار کے تسلط، مغربی تہذیب و ثقافت کی یلغار اور صلیبی عقائد و تعلیم کی ترویج کے دور میں یہ مدارس ملی غیرت اور دینی حمیت کا عنوان بن کر سامنے آئے اور انہوں نے انتہائی بے سروسامانی کے عالم میں سیاست، تعلیم، معاشرت، عقائد اور تہذیب و ثقافت کے محاذوں پر فرنگی سازشوں کا جرأت مندانہ مقابلہ کر کے برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش کو اسپین بننے سے بچا لیا ۔ اور یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج اس خطہ زمین میں مذہب کے ساتھ وابستگی اور اسلام کے ساتھ وفاداری کے جن مظاہر نے کفر کی پوری دنیا کو لرزہ براندام کر رکھا ہے، عالم اسباب میں اس کا باعث صرف اور صرف یہ دینی مدارس ہیں۔
قرآنِ کریم اور سود
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
قرآنِ کریم میں خلافتِ الٰہیہ کے قیام سے مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک ایسی قوت پیدا کی جائے جس سے اموال اور حکمت، علم و دانش دونوں کو لوگوں میں صرف کیا جائے اور پھیلایا جائے۔ اب سودی لین دین اس کے بالکل منافی اور مناقض ہے۔ قرآن کریم کی قائم کی ہوئی خلافت میں ربوٰا (سود) کا تعامل کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا جواز بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نور و ظلمت کا اجتماع۔ ربوٰا(سود) سود خواروں کے نفوس میں ایک خاص قسم کی خباثت پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر یہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے سامنے اس کا ’’اضعافًا مضاعفًا‘‘ نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں سود کی وجہ سے اقتصادیات میں جو فساد اور اخلاقِ فاضلہ کی تباہی اور بربادی اور فطرتِ انسانیہ میں بگاڑ اور لوگوں پر ضیق و تنگی پیدا ہوتی ہے، یہ اس قدر ظاہر باتیں ہیں جن کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے قرآنِ عظیم نے سود کو روئے زمین سے مٹانے کا اعلان کیا ہے اور انسانیت کو اس کے لینے دینے والوں کے شر و ظلم سے چھڑانے کا اعلان کیا ہے۔
سب سے پہلے مواعظِ حسنہ کے ذریعے سودی کاروبار سے منع کیا ہے۔ اگر اس سے باز نہ آئیں اور متنبہ نہ ہو تو ان کے ساتھ سخت لڑائی کا اعلان کیا ہے اور ایسے لوگوں کو سطحِ ارضی سے مٹانے کا چیلنج کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی اساسی تعلیم بڑے محکم طریق پر دی ہے۔ ربوٰا سے منع کیا گیا ہے، سود خواروں کے خلاف اعلانِ جنگ کیا ہے، لیکن پوری طرح رشد و ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور اس کی مضرتوں کو پوری طرح کھول کر بیان کر دینے کے بعد جو کرے، یہ رشد و ہدایت کے یقیناً منافی ہے۔ اب اس کے خلاف جنگ یا کارروائی کرنا اکراہ نہیں ہو گا بلکہ عین انصاف کا تقاضا ہو گا۔ اسی طرح ایسی بڑی بڑی حکومتوں کو مٹانا اور منہدم کرنا ہے جو اس کے لیے منظم کی جاتی ہیں کہ سودی کاروبار کے ذریعے اموال کمائیں، ان کے خلاف خدا اور رسولؐ کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔
(الہام الرحمٰن)
تعارف و تبصرہ
ادارہ
خطباتِ صدارت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ برصغیر پاک و ہند بنگلہ دیش کی وہ نابغۂ روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے علمی، روحانی اور سیاسی میدان میں ملک و قوم کی بے پناہ خدمت کی اور تحریکِ آزادی میں مؤثر اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ حضرت مدنیؒ نے سالہا سال تک مسجدِ نبویؐ میں روضۂ اطہر علٰی صاحبہا التحیہ والسلام کے سامنے حدیثِ رسولؐ کا درس دیا اور ہزاروں تشنگانِ علوم کو سیراب کیا۔ انہوں نے اپنے عظیم استاذ شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کے ساتھ مالٹا کی قید کاٹی اور رہائی کے بعد متحدہ ہندوستان میں آزادیٔ وطن کی جدوجہد کی قیادت سنبھالی۔
جمعیۃ العلماء ہند اس خطہ کے حریت پسند علماء کی جماعت ہے جس نے آزادیٔ وطن کی خاطر مسلسل جدوجہد کی۔ اس عظیم کردار کی حامل جماعت کی قیادت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کے ہاتھ میں تھی۔ جمعیۃ العلماء ہند کے سالانہ اجتماعات متحدہ ہندوستان کے علماء کرام کے ملک گیر نمائندہ اجتماع ہوتے تھے جن کے فیصلے اور خطباتِ صدارت قومی سیاست میں اپنی ایک مخصوص حیثیت رکھتے تھے۔ ان اجتماعات میں ملک کی نامور علمی اور قومی شخصیات کو صدارت کی زحمت دی جاتی اور ان کے خطبہ ہائے صدارت قومی سیاست اور تحریکِ آزادی میں فکری راہنمائی کا ذریعہ بنتے۔ جمعیۃ کے مختلف قومی اور علاقائی اجتماعات میں حضرت مدنیؒ نے بھی خطبات ارشاد فرمائے۔ ان کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا اور جب وہ تاریخی حوالوں اور معاشی اعداد و شمار کے ساتھ آزادی کی اہمیت اور فرنگی حکمرانوں کے مظالم کو بے نقاب کرتے تو ان کے مضبوط دلائل کے سامنے فرنگی سازشوں کے تار و پود بکھر کر رہ جاتے۔
مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے مہتمم حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ العالی نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کے گیارہ خطباتِ صدارت کو اس مجموعہ میں یکجا کر کے شائع کیا ہے جو ۱۹۲۱ء سے ۱۹۵۱ء تک جمعیۃ العلماء ہند کے تاریخی کردار کے ساتھ ساتھ اس دور کے حالات اور سیاسی پس منظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ پانچ سو صفحات پر مشتمل یہ مجموعہ معیاری کتابت و طباعت کے ساتھ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے اور اس کی قیمت ۸۰ روپے ہے۔
تسہیل الادب (جزء اول)
تالیف: مولانا سلیم اللہ خان
کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات ۱۱۰
ناشر: جامعہ فاروقیہ (پوسٹ بکس ۱۱۰۲۰) شاہ فیصل کالونی ۴ کراچی ۴۵
حضرت مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ کا شمار ملک کے نامور اساتذہ میں ہوتا ہے جن کی زندگی کا بیشتر حصہ تعلیم و تدریس میں گزرا ہے۔ انہوں نے درجۂ اول کے طلبہ کے لیے ’’تسہیل الادب‘‘ کے نام سے یہ مجموعہ ترتیب دیا ہے جس کا جزء اول ہمارے سامنے ہے۔ اس میں نحو کے ضروری مسائل اور اصطلاحات کو مبتدی طلبہ کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تمرینات کے ذریعے اس کی کوشش کی گئی ہے کہ طلباء کے اذہان مسائل کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی مشق بھی اچھے انداز سے کر سکیں۔ مبتدی طلبہ کے لیے اس قسم کے رسائل کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ کی یہ کاوش اس سمت ایک اچھی پیشرفت ہے۔
امام اعظم ابوحنیفہؒ کا نظریہ انقلاب و سیاست
از: مولانا عبد القیوم حقانی
کتابت و طباعت عمدہ۔ قیمت ۶ روپے صفحات ۶۸
ملنے کا پتہ: مؤتمر المصنفین، دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک ضلع پشاور
امام اعظم ابوحنیفہؒ اُمت مسلمہ کے عظیم المرتبت فقیہ اور مجتہد ہونے کے علاوہ اپنے وقت کے بلند حوصلہ سیاسی راہنما بھی تھے اور انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم اور بدعنوانیوں کو بے نقاب کرنے اور اصلاح و انقلاب کی تحریکات کی سرپرستی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ امام ابوحنیفہؒ نے نہ صرف عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کو اس کے دربار میں کھڑے ہو کر ان الفاظ سے للکارا کہ’’ تمہاری حکومت شرعی اور آئینی نہیں ہے، جب تم نے خلافت سنبھالی تو اس وقت اربابِ فتوٰی دو آدمی بھی تمہاری خلافت پر متفق نہیں تھے‘‘ بلکہ خلیفہ منصور کے خلاف حضرت زید بن علیؓ اور حضرت نفس زکیہؒ کی انقلابی تحریکات کو جہاد قرار دیتے ہوئے ان میں شرکت کو پچاس حج سے افضل بتایا اور ان کے حق میں باقاعدہ فتوٰی جاری کیا۔
امام اعظمؒ کی انقلابی سیاسی زندگی کا یہ پہلو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا جبکہ آج کے دور میں امام صاحبؒ کے سیاسی و معاشی افکار کو زیادہ سے زیادہ وضاحت اور اہمیت کے ساتھ سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فاضل دوست مولانا عبد القیوم حقانی کا ذوق قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اس کتابچہ میں امام اعظمؒ کے سیاسی افکار اور انقلابی جدوجہد کو اجاگر کرنے میں کامیاب کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں اور ان کی اس کاوش کو علماء کرام میں سیاسی شعور کی بیداری کا ذریعہ بنائیں، آمین یا الٰہ العالمین۔
تنقید اور حقِ تنقید
از: مولانا محمد یوسف لدھیانوی
صفحات ۳۲ قیمت ۴ روپے
ملنے کا پتہ: سنی تحریک طلبہ، مدینہ بازار، ذیلدار روڈ، اچھرہ، لاہور
’’جماعتِ اسلامی‘‘ کی بنیاد اس کے دستور کی دفعہ ۶ کے حوالہ سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معیارِ حق اور تنقید سے بالاتر نہ سمجھنے پر رکھی گئی تھی اور بانیٔ جماعتِ اسلامی اور ان کے رفقاء نے اس فکری بنیاد پر اس قدر ثابت قدمی دکھائی کہ اس کے دفاع میں اہلِ سنت کے ساتھ مستقل محاذ آرائی کا بازار گرم کر لیا۔ جبکہ یہ دونوں باتیں اہل سنت والجماعت کے مسلّمات کے منافی ہیں اور اہل سنت کے نزدیک حضرات صحابہ کرامؓ نہ صرف معیارِ حق ہیں بلکہ طعن و تنقید سے بھی بالاتر ہیں۔
مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے بانیٔ جماعتِ اسلامی کے ایک عقیدت مند کے استفسار پر اپنے مفصل مکتوب میں اہلِ سنت کے اسی نقطۂ نظر کی وضاحت کی ہے اور تنقیدی فکر کی کجی کو دلائل کے ساتھ آشکارہ کیا ہے۔ مولانا لدھیانوی کے مکتوب کو سنی تحریک طلبہ کی طرف سے زیرنظر رسالہ کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔
آپ نے پوچھا
ادارہ
قادیانی اور مسئلہ کشمیر
سوال: عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پیدا کرنے میں قادیانیوں کا ہاتھ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ (حافظ محمد ایوب گوجرانوالہ)۔
جواب: یہ بات تاریخی لحاظ سے درست ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب پاکستان کے قیام اور ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ پنجاب کی تقسیم کا بھی فیصلہ ہو گیا تو پاکستان کے حصے میں آنے والے پنجاب کی حد بندی کے لیے ریڈکلف باؤنڈری کمیشن قائم کیا گیا جس نے متعلقہ فریقوں کا مؤقف معلوم کرنے کے بعد حد بندی کی تفصیلات طے کر دیں۔ اصول یہ طے ہوا تھا کہ جس علاقہ میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گی وہ پاکستان میں شامل ہو گا اور جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہو گی وہ بھارت میں رہے گا۔
ضلع گورداسپور کی صورتحال یہ تھی کہ قادیانیوں کا مرکز ’’قادیان‘‘ اس ضلع میں تھا اور ان کی بڑی آبادی بھی یہیں تھی۔ اگر ان کی آبادی کو مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا جاتا تو یہ علاقہ مسلم اکثریت کا علاقہ شمار ہوتا اور اگر انہیں غیر مسلموں کے زمرہ میں رکھا جاتا تو یہ غیر مسلم اکثریت کا علاقہ تھا۔ قادیانیوں نے باوجود اس کے کہ وہ خود کو مسلمان کہنے پر ابھی تک مصر ہیں اور اسلام کے نام پر اپنے جھوٹے مذہب کے فروغ میں مصروف ہیں، ریڈ کلف کمیشن کے سامنے اپنا مؤقف مسلمانوں سے الگ پیش کیا جس کی وجہ سے اس علاقہ کو غیر مسلم اکثریت کا علاقہ قرار دے دیا گیا اور اسے بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ ضلع گورداسپور کی جغرافیائی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کو بھارت سے ملانے والا واحد راستہ ضلع گورداسپور سے ہو کر جاتا تھا۔ اگر یہ ضلع پاکستان میں شامل ہوتا تو بھارت کے پاس کشمیر میں مداخلت کا کوئی زمینی راستہ نہیں تھا۔ اس طرح کشمیر بھارت کی دستبرد سے محفوظ رہتا۔
اس پس منظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں نے ریڈکلف کمیشن کے سامنے اپنا مؤقف مسلمانوں سے الگ پیش کر کے ضلع گورداسپور کو بھارت میں شامل کرنے کا موقع فراہم کیا جس سے بھارت کو کشمیر کے لیے راستہ ملا اور اس نے مداخلت کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس لحاظ سے کشمیر اور اہلِ کشمیر کی موجودہ غلامی اور مصائب کی ذمہ داری قادیانیوں پر عائد ہوتی ہے۔
خارجی گروہ کب پیدا ہوا؟
سوال: خارجی گروہ کسے کہتے ہیں اور اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ (محمد اسلم، اسلام آباد)
جواب: امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین کے درمیان مصالحت کی بات چلی اور دونوں لشکروں نے جنگ بندی کر کے حضرت ابو موسٰی اشعریؓ اور حضرت عمرو بن العاصؓ کو مصالحتی گفتگو کے لیے ثالث مقرر کر لیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کا ایک حصہ ان کے اس فیصلہ پر ناراض ہو کر الگ ہو گیا۔ اس وقت ان کی تعداد کم و بیش بارہ ہزار تھی اور ان کا موقف یہ تھا کہ حکم صرف خدا کا ہے اور دو انسانوں کو حکم اور فیصل مقرر کر کے فریقین نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت علیؓ کی بیعت توڑ کر عبد اللہ بن وہب الراسبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
حضرت علیؓ نے مختلف صحابہ کرامؓ کے ذریعے اور براہ راست ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے بلکہ حضرت علیؓ کے مقابلہ پر لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ نہروان کے مقام پر حضرت علیؓ کے لشکر سے ان کی جنگ ہوئی جس میں خوارج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد کسی علاقہ پر اس گروہ کا تسلط تو نہ رہا لیکن ایک مذہبی فرقہ کی حیثیت سے اس کا وجود کافی عرصہ تک قائم رہا۔
ان کے عقائد میں یہ بات نمایاں تھی کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ کی تکفیر اور توہین میں یہ لوگ نمایاں تھے۔ آج دنیا میں خوارج کا کوئی منظم فرقہ موجود نہیں ہے لیکن حضرت علیؓ اور اہلِ بیتؓ کے بارے میں غیر متوازن نظریات کے حامل افراد کو الزاماً خارجی کہہ دیا جاتا ہے۔
متعہ اور امام مالکؒ
سوال: متعہ کسے کہتے ہیں اور کیا اہلِ سنت کے کسی امام کے نزدیک متعہ جائز ہے؟ (عبد الحمید، لاہور)
جواب: مرد اور عورت کے درمیان عمر بھر کے لیے ازدواج کا جو عقد ہوتا ہے وہ شرعاً نکاح کہلاتا ہے اور ازدواج کی شرعی شکل ہے۔ لیکن اگر اسی عقد کی مدت متعین کر دی جائے تو اسے متعہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اتنے دن کے لیے یا ماہ کے لیے یا سال کے لیے نکاح کیا جائے۔ مدت خواہ ایک گھنٹہ ہو یا پچاس سال، جب نکاح میں مدت طے کر دی جائے تو وہ متعہ بن جاتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں متعہ بھی ازدواج کی جائز صورتوں میں شمار ہوتا تھا لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اہلِ تشیع اس کے جواز کے قائل ہیں مگر اہلِ سنت کے نزدیک متفقہ طور پر حرام ہے اور کوئی امام بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ بعض فقہاء نے حضرت امام مالکؒ کی طرف متعہ کے جواز کی نسبت کی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ خود حضرت امام مالکؒ متعہ کی حرمت کے قائل ہیں اور مؤطا امام مالک میں انہوں نے متعہ کی حرمت پر روایات بھی نقل کی ہیں۔
بے نماز کی قربانی
سوال: ایک شخص نماز روزہ کی پابندی نہیں کرتا مگر زکوٰۃ اور قربانی ادا کرتا ہے، کیا اس کو اس عمل کا ثواب ہو گا؟ (حافظ محمد سعید، گوجرانوالہ)
جواب: اگر وہ نماز روزہ کا منکر نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اس پر اسے ثواب ملے گا اور جن فرائض کا تارک ہے اس پر اسے گناہ ہو گا اور وہ اس کے ذمہ واجب الادا رہیں گے جب تک کہ ان کی قضا نہ کر لے۔
برص ۔ انسانی حسن کو زائل کرنے والا مرض
حکیم محمد عمران مغل
اس مرض کو عوام اپنی زبان میں سفید داغ، پھلبہری، چٹاک وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سفید داغ جسم پر نمودار ہوا کرتے ہیں جسے طبی زبان میں برص کہا جاتا ہے۔ رفتارِ زمانہ کے ساتھ اس مرض میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیہاتیوں کی نسبت شہر میں رہنے والے کچھ زیادہ ہی اس کے گھیرے میں آ رہے ہیں۔ اس مرض کا خاص سبب تو عصبی خرابی ہے۔ جگر کی خرابی اور کمزوری کے ساتھ معدہ کی فاسد رطوبتیں بھی اس مرض میں اضافہ کا موجب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید تہذیب کی کچھ خاص رسمیں اور عادات بھی اس میں اضافہ کر رہی ہیں۔ مثلاً شہروں میں دودھ دہی کی دکان پر آپ کھڑے ہیں اور دودھ پینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ دودھ والے نے فورًا کھولتے دودھ میں برف ملا کر ٹھنڈا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا۔ ایک تو کھڑا ہو کر پینے سے جگر میں کمزوری پیدا ہوئی، پھر دودھ میں وہ تازہ ہوا یا آکسیجن جذب نہ ہو سکی جو قدرتی طور پر عام ہوا میں رکھنے سے ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ایسا دودھ لازمی بلغم کی کثرت کا باعث بنے گا۔ چنانچہ تمام بازاری آئس کریم اور قلفیوں کا یا دودھ کی مصنوعات کا یہی حال ہے۔ اس سے جو بلغم پیدا ہو گا اس میں خون بننے کی صلاحیت نہیں ہوا کرتی (کچی بلغم تقریباً سارا خون ہی ہوا کرتا ہے)۔
ہمارے جسم میں قدرت نے بہت سی قوتیں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک قوت کا نام قوتِ ممیزہ ہے، یہی قوت بلغم سے خون بناتی ہے مگر وہ بلغم اپنی تعریف پر پورا اترتا ہو۔ ایسے خواتین و حضرات جن کا جگر اور معدہ اکثر خراب رہتا ہو اور مزاج بھی بلغمی ہو تو ان میں اس مرض کو قبول کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ زیادہ سرد غذائیں، چاول، بادی اشیاء اور کئی کئی دنوں کی پکی ہوئی غذا جسے فریج میں رکھ دیا گیا ہو کھانے سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسی غذا جس میں بلی، چوہا، چھپکلی منہ مار جائے، یا پیتل تانبے کے برتن میں کھانا کھانا جبکہ اسے قلعی نہ کرائی گئی ہو۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ پینا، گلی سڑی باسی مچھلی کھانا، مٹھائی یا فروٹ کھا کر پانی پینا اور پہلی غذا پوری طرح ہضم نہ ہو اوپر سے اور ٹھونس لینا، یہ تمام اسباب اس مرض کو دعوت دیتے ہیں۔ مخلوقِ خدا کی بہتری کے لیے حکماء متقدمین نے ایک نصیحت فرمائی ہے ؎
جب بھوک لگے تب کھاؤ
کچھ بھوک رہے ہٹ جاؤ
اور یہ نصیحت علاج کے ساتھ سونے پر سہاگہ کا کام دیتی ہے۔ شروع میں باریک باریک دانے نکلتے ہیں جو پھیل کر سفید داغ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مرض اور بھی ہے جسے بہق ابیض کہتے ہیں۔ مگر برص میں رنگت سفید اور جلد چکنی ہو گی۔ بعض دفعہ یہ مرض جلد سے ہوتا ہوا ہڈی تک چلا جاتا ہے۔ وہاں کا بال بھی سفید ہو جاتا ہے اور سوئی چبھونے سے خون کی بجائے زردی مائل پانی نکلتا ہے۔ اب علاج ذرا دیر سے ہو گا۔ یاد رکھیں کہ طبِ یونانی اور اسلامی میں دس دس سال کے مریض شفایاب ہوئے ہیں۔
علاج
سب سے پہلے بسیار خوری اور نازک مزاجی کو ختم کر کے صبح شام سیر کریں اور کوشش کریں کہ کام کاج سے پسینہ خوب خارج ہو کیونکہ ؎
اچھی نہیں نزاکتِ احساس اس قدر
شیشہ اگر بنو گے تو پتھر بھی آئے گا
قابض اور تمام بادی اشیاء سے پرہیز اور تمام ایسی اشیاء جن کی رنگت سفید ہو بالکل بند کر دیں۔ احقر نے اس اصول کے تحت کامیاب علاج کیا ہے:
(۱) کھانے کے بعد صبح شام چھ ماشہ جوارش جالینوس ہمراہ تازہ پانی یا عرق بادیان۔ جگر کی اصلاح کے لیے کسی بھی دواخانہ کی کوئی سی دوا کھائی جا سکتی ہے۔
(۲) اجمود تازہ چار ماشہ صبح نہار منہ تازہ پانی سے کھائیں اور روزانہ سوا ماشہ اضافہ کرتے کرتے آٹھ ماشہ تک کریں۔ اب آٹھ ماشہ ایک ماہ تک کھائیں۔ ان شاء اللہ برص بیخ و بن سے اکھڑ جائے گا، برف کا قطعی پرہیز ہونا چاہیئے۔
عمل کا معجزہ حق ہے سکوت و ضبط باطل ہے
سرور میواتی
وطن کی خستگی وجہِ شکستِ بربطِ دل ہے
وطن کی اس تباہی میں ’’انا‘‘ کا ہاتھ شامل ہے
چمن کی رونقیں سب نذرِ صَرصَر ہوتی جاتی ہیں
نہ شادابی گلوں میں ہے نہ گل بانگِ عنادل ہے
شکستہ جام و مینا خشمگیں ساقی سبو خالی
یہ بزمِ ذی شعوراں ہے کہ دیوانوں کی محفل ہے
امنگیں مرثیہ خواں ہیں تمنائیں ہیں پژ مُردہ
حُدی خواں گنگ بیچارہ نہ ناقہ ہے نہ محمل ہے
تلاطم خیز دریا ہے سفینے کا خدا حافظ
ہے نوآموز کشتی باں نہاں نظروں سے ساحل ہے
جمالِ آشتی سے ہے مزاجِ یار بے گانہ
رعونت اُس بتِ طنّار کی فطرت میں شامل ہے
نہ ہو جائیں کہیں دہلیز و در ہی نذرِ ہنگامہ
نہ یہ گرنے پہ آمادہ نہ وہ جھکنے پر مائل ہے
دلِ نازک میں ہو پیدا کہاں سے ہمتِ مرداں
انانیت کی جب اس راہ میں دیوار حائل ہے
ہوا کا رخ پلٹ دے ہمت و تدبیر سے سرور
عمل کا معجزہ حق ہے سکوت و ضبط باطل ہے
تعلیم کے دو طریقے
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کو دو مختلف طریقوں سے تعلیم دینی پڑتی ہے: ایک یہ کہ لوگوں کو ان باتوں کی تعلیم دے جو ان کے اخلاق کو درست کریں، اور اقامتِ خیر اور رائے سلیم پر مبنی معاشرتی زندگی بالخصوص ارتفاقِ ثانی و ثالث کے نظام کو اس طریقہ سے قائم کرنے میں مدد دیں جو رائے صواب کے مطابق ہو۔ دوسرے یہ کہ ان کو ان باتوں کی تعلیم دے جن کے ذریعے وہ خدائے بزرگ و برتر کا قرب حاصل کریں اور دارِ آخرت میں ان کی نجات و سعادت کے باعث ہوں۔
ایک دوسری تقسیم کے مطابق خیر کی تعلیم دو طریقوں سے دی جا سکتی ہے:
(۱) جن باتوں کے ذریعے ان کی دنیا سنورتی ہے اور جن باتوں سے ان کو بارگاہِ الٰہی میں تقرب حاصل ہوتا ہے ان تمام باتوں کی تعلیم دینا، جو زبانی وعظ و تذکیر کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے اور قلم و تحریر کے ذریعے بھی ان مسائل کی اشاعت کی جا سکتی ہے۔
(۲) ان کے باطن میں پاکیزہ حالت پیدا کر دینا جس کو سکینہ اور طمانیتِ قلب کہا جاتا ہے اور جس کی تشریح ہے کہ آدمی کا دل ہر وقت آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ دارِ غرور یعنی دنیا سے اعراض اور بے تعلقی پیدا ہوتی ہے، نیز ان امور سے بھی لا تعلقی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو دنیاوی زندگی سے نفس کی کُلّی وابستگی کے ذرائع ہیں۔ یہ پاکیزہ حالت معلم کبھی تو مؤثر پند و نصیحت کے ذریعے پیدا کرتا ہے اور کبھی اپنی پاکیزہ مجلس و صحبت اور روحانی توجہ کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔
معلم ان دونوں میں سے جو بھی قسم یا طریقۂ تعلیم اختیار کرے اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ خود عادل و منصف مزاج اور کامل ترین نمونۂ اخلاق ہو، اور آخرت کی نجات و سعادت کو دنیا اور دنیا کی عیش و عشرت پر ترجیح دینے والا ہو۔
(البدور البازغۃ مترجم)
دینی و عصری تعلیم کے امتزاج کیلئے چند تجاویز
شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
(شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۲۸۔۲۹ مارچ ۱۹۳۷ء کو علی گڑھ میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی پچاس سالہ جوبلی کے موقع پر شعبہ مدارس اسلامیہ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دینی مدارس کے طلبہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنے خطبۂ صدارت میں مندرجہ ذیل تجاویز پیش فرمائیں جو نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اپنی افادیت و اہمیت کے لحاظ سے سنجیدہ توجہ کی متقاضی ہیں — ادارہ)
(۱) کچھ کچھ معتد بہ وظائف ان طلبہ کے لیے مقرر کیے جائیں جو عربی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انگریزی پڑھنا چاہیں۔ اور علٰی ہذا القیاس انگریزی مدارس کے ان فارغ شدہ طلبہ کے لیے بھی، جو عربی پڑھنا چاہیں، ان کے لیے بھی وہ وظائف امدادیہ جاری کیے جائیں۔
(۲) جس طرح مولوی فاضل وغیرہ کے سند یافتہ صرف زبانِ انگریزی میں گورنمنٹی امتحانات میں شرکت حاصل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح مسلم یونیورسٹی اپنے یہاں ایسے قوانین بنائے جن کے رو سے عربی مدارس کے فارغ شدہ طلبہ صرف انگریزی زبان کے امتحان میں شامل ہو سکیں۔ ان کے لیے تعلیم کا مستند انتظام کیا جائے کہ ایف اے کے بعد وہ بی اے کا امتحان دے سکیں۔
(۳) عربی مدارس کے طلبہ کے لیے ریلوے وغیرہ سے وہ تمام مراعاتیں ملنی چاہئیں جو انگریزی مدارس کے طلبہ یا ایڈگرفتہ مدارس کے طلبہ کو ملتی ہیں۔ ایجوکیشنل کانفرنس مستند مدارس عربیہ کی ایک فہرست تیار کرے جس کو گورنمنٹ بھی تسلیم کرے۔
(۴) قانون کے امتحانوں میں انگریزی زبان دانی کی شرط نہ رکھی جائے۔ امتحانات ملکی زبانوں میں ہوں۔ علمی استعداد شرط کی جائے مگر حسبٍِ مراتب جن امتحانوں کے لیے میٹرک، انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ کی شرط ہے وہ رکھی جائے۔ اور اسی درجہ کے عربی استادوں کو بھی کافی سمجھا جائے۔ عربی نصاب میں اس کے لیے مدارج قائم ہو سکتے ہیں اور بعض ضروری چیزوں کا نصاب میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
(۵) کورٹ کی لینگوئج بدل دی جائے۔ اگر فورًا ہائیکورٹ کی زبان بدلی نہ جا سکے تو وہ انگریزی ہی رہنے دی جائے لیکن دوسرے تمام کورٹوں کی زبان لازمی طور پر بدل دی جائے۔
(۶) رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں عربی کی اسناد کو بھی ملازمت کے لیے کافی سمجھا جائے۔
(۷) اوقاف کے تمام ذمہ دار عہدوں کے لیے عربی اور مذہبی تعلیم کی تکمیل ضروری سمجھی جائے اور شرط کر دی جائے۔
(۸) محکمہ منصفی اور ججی (صدارتِ اعلٰی) کے لیے، جس میں قضاء شرعی اور تقسیمِ وراثت وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، مذہبی تعلیم کی سند ضروری قرار دی جائے۔
(۹) مسلمانوں کو محکمہ قضاء حسبِ طلب عطا کیا جائے جس کا مطالبہ عرصہ دراز سے مسلمان کر رہے ہیں۔
(۱۰) آرٹ اور صنعت کی تعلیم میں عربی تعلیم کے سند یافتوں کو شرکت کا موقع دیا جائے۔
(۱۱) محکمہ ہائے انہار، زراعت، تجارت کی تعلیمات میں عربی تعلیم یافتوں کو شریک کیا جائے۔
(۱۲) یونیورسٹیوں کے وہ طلبہ جو عربی پڑھتے ہیں تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے کسی عربی دینی مدرسہ میں جا کر قیام کیا کریں اور عربی کی اعلٰی تعلیم سے استفادہ کریں۔
اگست ۱۹۹۰ء
ایک اور ’’دینِ الٰہی‘‘؟
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
روزنامہ جنگ لاہور ۲۰ جولائی ۱۹۹۰ء کی رپورٹ کے مطابق حکمران پارٹی کی سربراہ بیگم بے نظیر بھٹو نے لاہور ایئرپورٹ پر اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے شریعت بل کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ:
’’ہم ایسا اسلام چاہتے ہیں جو واقعی اللہ کی ہدایات کے مطابق ہو۔ پوری دنیا اللہ کی ہے۔ عوام اللہ کے نمائندے ہیں۔ منتخب پارلیمنٹ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھیں گے۔ ہم انسانوں کے کان یا ہاتھ کاٹنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔‘‘
قومی اسمبلی میں ’’شریعت بل‘‘ کے زیر بحث آنے سے قبل حکمران پارٹی کی سربراہ کا یہ بیان جہاں حکمران پارٹی کی پالیسی اور عزائم کی عکاسی کرتا ہے وہاں ملک کے دینی حلقوں کے لیے یہ لمحۂ فکریہ بھی مہیا کرتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگ ڈور ہے اسلام کے بارے میں خود ان کا نقطۂ نظر کیا ہے اور وہ اسلام کا نام لے کر ملک کو کس ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں۔ بیگم بے نظیر بھٹو اور ان کے وزیر قانون اس سے قبل بھی اسلامی قوانین اور شرعی حدود کو متعدد مواقع پر وحشیانہ اور انسانی حقوق کے منافی قرار دے چکے ہیں اور اب پھر قدرے نرم الفاظ کے ساتھ ان کی طرف سے اسی موقف کا اظہار کیا گیا ہے۔
ہم اس موقع پر حکمران پارٹی سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ’’اللہ تعالیٰ کی واقعی ہدایات‘‘ حاصل کرنے کے متبادل ذرائع آخر کونسے ہیں؟ کیونکہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں ان میں ہاتھ، کان، ناک اور دیگر اعضا (بطورِ قصاص) کاٹنے کے واضح احکام موجود ہیں اور شرعی احکام کے بارے میں پارلیمنٹ یا کسی بھی انسانی ادارہ کی بالادستی کی قطعی نفی کر دی گئی ہے۔ کہیں اکبر بادشاہ کی طرح یہ ’’نیا دینِ الٰہی‘‘ نافذ کرنے کا پروگرام تو نہیں؟ حکمران پارٹی کو یہ بات ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اکبر بادشاہ کے درباری اجتہاد یا مرزا غلام احمد قادیانی کی خود ساختہ وحی کے ذریعے شرعی احکام کو بدلنے کا کوئی تجربہ یہاں نہیں چل سکتا اور نہ ہی واشنگٹن، لندن اور ماسکو کے افکار و نظریات پر اسلام کا لیبل لگا کر انہیں ملک کے عوام سے قبول کروایا جا سکتا ہے۔
جمہوریت، قرآن کریم کی روشنی میں
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
قلت و کثرت کا مسئلہ اکثر انسانی اذہان میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہے ’’قُلْ‘‘ اے پیغمبرؐ! آپ کہہ دیجئے ’’لَا یَسْتَوِی الْخَبِیْثُ وَالطَّیِّب‘‘ خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ پاک اور ناپاک چیز یکساں نہیں۔ ’’وَلَوْ اَعْجَبَکَ کَثْرَۃُ الْخَبِیْث‘‘ اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے۔ اگر دنیا میں کفر، شرک، معاصی اور گندے نظام کا غلبہ ہو، دنیا میں ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ کا دور دورہ ہو، تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ اچھی اور خدا کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کلمۂ حق ہی اچھا ہے اگرچہ دنیا میں اس کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو۔
مثال کے طور پر اگر دنیا کا بیشتر حصہ حرام سے بھرا ہوا ہے اور حلال کا حصہ بالکل کم ہے تو حرام کی کثرت اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نزدیک حلال ہی پسندیدہ ہے خواہ وہ کتنی قلت میں ہو۔ اگر ایک مومن آدمی اپنی محنت کے ذریعے پانچ روپے رزق حلال کماتا ہے تو وہ اس سو روپے سے زیادہ بہتر ہیں جو رشوت کے ذریعے حاصل کیے گئے ہوں۔ اسی طرح جائز کمائی کے سو روپے سود کے ایک لاکھ روپے سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ سو روپے ہی محبوب ہیں۔ اسی طرح اگر دنیا میں اچھے اخلاق والے قلیل تعداد میں ہیں تو اکثریت کے مقابلے میں وہی کامیاب ہیں۔ عقل مندوں کی قلیل تعداد بیوقوفوں کے جم غفیر سے بدرجہا بہتر ہے۔
یورپ کی جمہوریت کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں انسانوں کی قابلیت کی بجائے ان کی تعداد کو معیار بنایا گیا ہے، جو زیادہ ووٹ حاصل کرے وہی کامیاب ہے اگرچہ خود ووٹر معیار سے گرے ہوئے لوگ کیوں نہ ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی تو کہا تھا ؎
از مغز دو صد خر فکرِ انسانے نمی آید
یعنی دو سو گدھے ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگرچہ وہ غالب اکثریت میں ہیں۔ ہاں اگر طیب اور پاک چیز ہے تو وہ نورٌ علیٰ نور ہے۔ اور اگر گندی چیز یا گندہ نظام اکثریت میں ہے تو اس سے گبھرانا نہیں چاہیئے۔ بری چیز بہرحال بری ہے محض اکثریت کی بنا پر اسے اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اس وقت پوری نیا کی پانچ ارب آبادی میں سے سوا چار ارب کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہے۔ ہر طرف امپریلزم، ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ کا دور دورہ ہے مگر کلمہ جامع نہیں ہے۔ ترکوں میں خلافت کے زمانے تک مسلمانوں میں کسی قدر اجتماعیت موجود تھی مگر انگریز نے بالآخر اسے ختم کر کے چھوڑا۔ اب مسلمانوں کا اجتماعی نظام بالکل ناپید ہے، حق مغلوب ہو چکا ہے اور باطل غالب ہے۔ مگر یہ اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے ہاں کلمہ حق، ایمان، اسلام اور پاکیزہ اخلاق ہی صداقت کا معیار ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ناپاک چیز بہرحال ناپسندیدہ ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنا بھی تعجب میں ڈال دے۔ انجام انہی لوگوں کا اچھا ہو گا جو حق پر ہیں خواہ وہ کس قدر قلیل تعداد میں ہوں۔
صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ قریب سے ایک اعلیٰ حیثیت کا آدمی گزرا۔ آپؐ نے صحابہؓ سے دریافت کیا، یہ کیسا آدمی ہے؟ آپؐ کو بتایا گیا کہ یہ اشراف میں سے ہے، جہاں جائے گا ہر شخص اس کے لیے گھر کا دروازہ کھولے گا، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے گا تو فورًا قبول کیا جائے گا، لوگ اس کے رشتہ پر فخر کریں گے، اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے گا تو قبول کی جائے گی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے شخص کا گزر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی دریافت فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فقراء میں سے ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں اور نہ کوئی اس کا احترام کرتا ہے، اگر کہیں جاتا ہے تو لوگ گھر کا دروازہ نہیں کھولتے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، کسی کی سفارش کرے تو کوئی پروا نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو! پہلے آدمی جیسے لوگوں سے اگر پوری زمین بھری ہوئی ہو تو اللہ کے نزدیک یہ دوسرا آدمی ان سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کے ہاں عزت و شرف کا معیار دنیاوی جاہ و جلال اور کثرت نہیں بلکہ ایمان اور تقوٰی ہے۔
بہرحال (قُل) فرما دیجیئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں اگرچہ کثرت کتنی ہی خوش کون کیوں نہ ہو۔۔۔حلال اور طیب کی قلیل مقدار حرام کی کثیر مقدار سے بہرصورت بہتر ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدگی کا معیار حق و صداقت ہے نہ کہ کثرتِ تعداد یا کثرتِ مقدار۔ فرمایا ’’وَاتَّقُوا اللہَ یَا اُولِی الْاَلْبَاب‘‘ اے صاحبِ عقل و خرد لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کی وحدانیت کے خلاف کوئی بات نہ کرو، اس کے بتلائے ہوئے پاکیزہ اصولوں پر عمل کرو۔ ’’لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْن‘‘ تاکہ تمہیں فلاح و کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان اصولوں پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو گی اور آخرت میں بھی نجات کا دارومدار اسی پر ہے۔
احادیث کی تعداد پر ایک اعتراض
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون میں ہم یہ بات عرض کر دیں کہ حضراتِ محدثین کرامؒ جب یہ فرماتے ہیں کہ فلاں کو دو لاکھ اور فلاں کو چھ لاکھ اور فلاں کو دس لاکھ احادیث یاد تھیں، تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کم فہم یا کج بحث آدمی تو اس کو جھوٹ یا مبالغہ ہی تصور کرے گا جیسا کہ چودھری غلام احمد صاحب پرویز نے طنزًا لکھا ہے:’’ایک صاحب بخارا سے آتے ہیں اور انہیں چھ لاکھ حدیثیں مل جاتی ہیں جن میں سے وہ قریباً سات ہزار کو اپنے مجموعہ میں داخل کر لیتے ہیں، ان کے اساتذہ میں سے امام احمد بن حنبلؒ دس لاکھ اور امام یحیٰی بن معینؒ بارہ لاکھ حدیثوں کے مالک تھے ۔۔ الخ‘‘ (مقامِ حدیث جلد دوم ص ۴۱۵)۔ دیکھیئے منکرینِ حدیث کا دورِ حاضر میں لیڈر کس طرح احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے؟ لیکن حقیقت شناس اس سے صحیح بات ہی سمجھتا ہے اور سمجھے گا۔ ذیل کے امور کو بغور دیکھیں:
(۱) تدوینِ کتبِ حدیث سے پہلے کا کوئی حوالہ ایسا موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ لاکھ یا اس سے زیادہ حدیثیں کسی کو یاد تھیں۔ کتبِ تاریخ اور کتبِ اسماء الرجال وغیرہا میں آپ صرف یہی پائیں گے کہ تدوینِ کتبِ حدیث کے زمانہ میں یا اس کے بعد ہی لوگوں کو لاکھ یا اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھیں۔ جن حضرات ائمہ کو لاکھ یا اس سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں مثلاً امام طیالسیؒ، امام عبدانؒ، امام ابن جعابیؒ، امام بخاریؒ، امام ابوزرعہؒ، اور امام احمد بن حنبلؒ تو ان کا دور تدوینِ حدیث اور اس کے بعد کا دور تھا۔ کتبِ حدیث کی مستقل تدوین اور فقہی ابواب پر ان کی ترتیب کے دور سے قبل اس قسم کا کوئی صریح حوالہ موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ فلاں بزرگ کو لاکھ یا اس سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، ایسے الفاظ آپ کو بعد کے ادوار کے ہی ملیں گے۔
(۲) امام حاکمؒ صاحبِ مستدرک اپنے مشہور رسالہ مدخل ص ۷ میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کی صحیح اور معیاری حدیثوں کے متعلق اگر چھان بین کی جائے تو ان کی تعداد دس ہزار تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی اگر غیر مکرر صرف مرفوع احادیث کا معیاری اور صحیح اسانید کے ساتھ شمار کیا جائے تو بمشکل تقریباً دس ہزار ہوں گی۔
(۳) مشہور محدث علامہ ابن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح حدیثوں کے ساتھ ساری بے بنیاد جھوٹی اور گھڑی ہوئی جعلی حدیثوں کو بھی جمع کر لیا جائے جو کتابوں میں مکتوب پائی جاتی ہیں تو وہ پچاس ہزار تک نہیں پہنچ سکتیں (کتاب صید الخواطر فصل ۱۷۵)
(۴) حضرات محدثینِ کرامؒ جب لفظ حدیث بولتے ہیں تو وہ اس سے مرفوع احادیث کے ساتھ حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؒ کے موقوفات اور آثار بھی مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ بیہقیؒ نے اس کی تصریح کی ہے (تہذیب التہذیب ج ۷ ص ۳۳)۔ اور ہم پہلے باحوالہ یہ عرض کر آئے ہیں کہ حضرات محدثین کرامؒ کو قراءت (تاریخ) وغیرہ سے متعلق بھی روایات مع سند یاد ہوتی تھیں، ان کو بھی وہ حدیث ہی کی مد میں شامل سمجھتے تھے۔
(۵) حضرات محدثین کرامؒ کی یہ جداگانہ اصطلاح ہے کہ اگرچہ متنِ حدیث ایک ہی ہو، جب اس کی سند اور سند کا کوئی ایک راوی بھی بدل جائے تو اس کو وہ اپنی اصطلاح میں الگ اور جداگانہ حدیث سمجھتے ہیں۔ چنانچہ محدث جعفر بن خاقانؒ کا بیان ہے کہ میں نے مشہور محدث امام ابراہیمؒ بن سعید الجوہری جو الحافظ اور العلامہ تھے (المتوفی ۴۴۱ھ) سے حضرت ابوبکرؓ کی ایک حدیث دریافت کی تو انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ جا کر حضرت ابوبکرؓ کی حدیثوں کی تئیسویں جلد نکال لاؤ۔ ابن خاقانؒ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ کیونکہ حضرت ابوبکرؓ سے بمشکل پچاس حدیثیں ہی ثابت ہیں تو انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی احادیث کا اتنا مجموعہ کیسے اور کہاں سے تیار کر لیا جن کی تئیس جلدیں بھی تیار کر لی گئیں۔ میں نے حضرت ابراہیمؒ سے پوچھا کہ بات کیا ہے، حضرت ابوبکرؓ کی اتنی حدیثیں کہاں سے آگئیں جن سے آپ نے تئیس جلدیں مرتب کر لی ہیں؟ حضرت ابراہیمؒ بن سعیدؒ نے جواب دیا کہ ایک ایک حدیث جب تک سو سو طریقوں اور سندوں کے ساتھ مجھے نہیں ملتی تو میں اس حدیث کے متعلق اپنے آپ کو یتیم خیال کرتا ہوں (تذکرہ ج ۲ ص ۸۹)۔ اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ حضرات محدثین کرامؒ جب تک ایک ایک حدیث کئی کئی اسانید اور طرق سے حاصل نہ کر لیتے دم نہ لیتے تھے اور ایسی صورت میں وہ خود کو یتیم تصور کرتے تھے۔
(۶) امام جلال الدین سیوطیؒ کے اس دعوٰی کی کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ایک محقق عالم نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ حضرات محدثین کرامؒ کی اصطلاح کے مطابق امام سیوطیؒ کی کتابوں میں ایک ایک حدیث اسانید کے لحاظ سے چار یا دس یا ساٹھ تک بھی پہنچ جاتی ہے (العلم المشائخ ص ۳۹۹۳)۔
(۷) علامہ ابن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ ’’ان المراد بھذا العدد الطرق لا المتون‘‘ احادیث کی تعداد اور گنتی میں اسانید اور طرق مراد ہیں نہ کہ متونِ حدیث۔ یہ حوالہ بھی اپنے مدلول اور مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔
قارئینِ کرام! ان مذکورہ بالا اصول اور قواعد کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس کا فیصلہ نہایت ہی سہل ہو جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں آپؐ سے حدیث سننے والے حضرات صحابہ کرامؓ تھے اور کوئی غیر صحابی راوی درمیان میں حائل نہیں ہوتا تھا، اس لیے احادیث کی تعداد بھی کم تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک سے بعد کی وجہ سے روات اور رجالِ سند کی کثرت سے تعداد بھی بڑھ گئی۔ اور اگر کہیں سند کا ایک راوی بھی بدل گیا تو تعداد کے لحاظ سے وہ حضرات محدثین کرامؒ کی اصطلاح میں الگ اور جدا حدیث بن گئی۔ اور اگر اس کے ساتھ حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے آثار موقوفات و فتاوٰی کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں اور توسیع ہو جاتی ہے۔
غرضیکہ جوں جوں سند طویل اور لمبی ہوتی جائے گی روات کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور ان کی تعداد کے مطابق احادیث و آثار کی تعداد اور گنتی بھی بڑھ جائے گی۔ حتٰی کہ متنِ حدیث میں کسی لفظ کے بدل جانے، یا کسی صحابی، یا نچلے روات میں سے کسی ایک راوی کے بدل جانے سے متن کے لحاظ سے ایک ہی حدیث ہو گی مگر گنتی کے حساب سے متعدد حدیثیں بن جائیں گی۔ مثلاً اگر کسی ایک محدث کو غیر مکرر ایک ہزار حدیث یاد ہے، اور ہر حدیث کے سو اور ساٹھ طرق اور سند میں نہ سہی اوسطاً دس طرق ہی ثابت ہو، تو حضرات محدثین کرامؒ کی اصطلاح میں گویا دس ہزار حدیثیں ہیں۔ یعنی حافظہ پر تو کُل دس احادیث میں سے ایک حدیث کے یاد کرنے کا بوجھ پڑا۔ باقی نو میں کہیں متن سے صرف ایک لفظ کا، کہیں سند میں کسی ایک راوی کے یاد کرنے کا بار پڑا، اور کہنے کو یہ کہہ لیا کہ دس ہزار حدیثیں ہو گئیں۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی نہ بھول جائیے کہ حسبِ تصریح امام سیوطیؒ اکثر احادیث (یعنی کافی مقدار میں) بالمعنی مروی ہیں (الاقتراح ص ۱۶)۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر نحاۃ الفاظِ حدیث سے قواعدِ نحویہ پر استدلال کو درست نہیں سمجھتے، اور جن لوگوں نے استدلال کیا ہے ان کی تغلیط کی گئی ہے (الاقتراح ص ۱۶)۔ اس نقل بالمعنی کے اصول کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اور توسیع ہو جاتی ہے کہ مثلاً کسی محدث نے اگر تشریح اور تفسیر کے طور پر ایک حدیث میں تشریحی الفاظ درج کر دیے جو اکثر آخر میں ہوتے ہیں (شرح نخبۃ الفکر ص ۶۲) تو ان کی اصطلاح میں یہ ایک الگ اور جداگانہ حدیث بن جائے گی جو تعداد اور گنتی میں الگ ہو گی۔
الحاصل جب حضرات محدثین کرامؒ کے نزدیک
- آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقاریر
- اور حضراتِ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے موقوفات اور آثار
- اور علمِ حدیث سے متعلق تاریخی واقعات اور شانِ نزول
- اور علمِ تجوید و قراءت سے متعلق اقوال اور تشریحات گنتی میں داخل ہیں
- اور سند میں صحابی اور نچلے کسی بھی راوی کے بدل جانے سے
- نیز متنِ حدیث میں معمولی تغیر سے جب روایت بدل جاتی ہے
- اور نقل بالمعنٰی کے پیشِ نظر جو تغیر واقع ہوتا
- اور تشریح و تفسیر کے طور پر جو الفاظ تفہیم کے لیے بڑھا دیے جاتے ہیں
- اور مزید برآں جعل سازوں کی بے شمار من گھڑت اور جعلی حدیثیں بھی اگر ان میں شامل کر لی جائیں (جبکہ حضرات محدثین کرامؒ ان کو اس لیے یاد کرتے تھے کہ عامۃ الناس ان پر عمل کر کے راہِ راست سے کہیں بھٹک نہ جائیں)
تو ان اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد احادیث کی کثرت پر جو خلجان واقع ہوتا ہے وہ خودبخود زائل ہو جاتا ہے۔ اور حضراتِ محدثین کرامؒ کی طرف نظر بہ ظاہر غلط بیانی یا مبالغہ آمیزی کی جو نسبت واقع ہوتی ہے کہ لاکھوں حدیثیں انہوں نے کہاں سے، کیسے اور کس طرح یاد کر لیں جب کہ نفس الامر میں اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں، تو وہ بالکل رفع ہو جاتی ہے۔ ایسا وہم صرف ان لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے جو اصل حقیقت سے شناسا نہیں یا اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں اور محدثینؒ پر بلا بیانِ اصلیت تنقید کرتے ہیں اور گویا وہ زبانِ حال و قال سے یہ کہتے ہیں کہ
طولِ شبِ فراق کا افسانہ چھیڑیے
لیکن بیانِ زلفِ پریشان نہ کیجئے
قارئینِ کرام یہ بات بخوبی معلوم کر چکے ہیں کہ متونِ احادیث کی تعداد لاکھوں تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ ہزاروں ہی میں منحصر ہے۔ چنانچہ جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے حضرت امام سفیان ثوریؒ، امام شعبہؒ بن الحجاجؒ، امام یحیٰی بن سعید ن القطانؒ، امام عبد الرحمٰن بن مہدیؒ، اور امام احمد بن حنبلؒ کا متفقہ فیصلہ ہے:
ان جملۃ الاحادیث المسندۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیحۃ بلا تکرار اربعۃ الآف و اربعۃ مأۃ حدیث۔ (توضیح الافکار ص ۶۲ طبع مصر الامیر الیمانیؒ)
اس حوالہ سے روز روشن کی طرح یہ بات آشکارا ہو گئی ہے کہ متونِ احادیث مرفوعہ صرف ہزاروں میں بند ہیں۔ ہاں تمام مرفوع اور موقوف آثار وغیرہ کو ملا کر اور حضراتِ محدثین کرامؒ کی اصطلاح کے موافق سند اور روات کو ملحوظ رکھ کر لاکھوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ حضراتِ صحابہ کرامؓ اور حضراتِ تابعینؒ کے زمانہ میں سند مختصر تھی اس لیے تعداد بھی کم تھی، اور فقہی ابواب پر کتبِ حدیث کی تدوین اور اس کے بعد کے دور میں چونکہ اسانید طویل ہو گئیں لہٰذا تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ طلبۂ علم کو یہ نکتہ ذہن سے نہیں نکالنا چاہیئے۔
ایک مسلم حکمران کیلئے جناب رسالتمآب ﷺ کی ہدایات
مولانا سید وصی مظہر ندوی
حضرت عمرو ابن حزم انصاری خزرجی ان نوجوان صحابیوں میں سے ہیں جن کے جوہرِ قابل کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوعمری ہی میں بڑی اہم ذمہ داریوں پر مامور فرمایا۔ ان کی عمر ابھی ۱۷ سال تھی کہ ان کو اہم سفارتی ذمہ داریوں پر مقرر کیا گیا۔ چنانچہ نجران کے وہ عیسائی پادری جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کے لیے آئے تھے اور جو اپنے علم پر بڑے نازاں تھے، ان کے علاقہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن حزم کو عامل (حاکم)، محصل (ریونیو افسر)، اور معلّم (مبلغ اور مربی) کی حیثیت سے بھیجا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف چند ماہ قبل ان کو نجران (یمن) میں گورنر مقرر کرتے ہوئے جو تحریری ہدایات دی تھیں ان کو امام ابو جعفر دیبلی سندھی متوفی ۳۲۲ھ نے ’’مکاتیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم‘‘ کے نام سے اپنے ایک مجموعہ میں شائع کیا ہے۔ یہ ہدایت نامہ حضرت عمرو ابن حزم کے خاندان میں محفوظ چلا آتا تھا، امام جعفر دیبلی کو ان کے پڑپوتے سے ملا ہے۔ حافظ ابن طولون نے اپنی کتاب ’’اعلام السائلین‘‘ میں امام ابوجعفر دیبلی کے پورے مجموعہ کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمرو ابن حزم کے نام یہ ہدایت نامہ بہت معمولی فرق کے ساتھ احادیث اور تاریخ کی اکثر کتابوں میں محفوظ ہے۔
حضرت عمرو ابن حزم کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدایت نامہ کا جو پس منظر بیان ہوا ہے اس سے ہدایت نامہ کی چند اہم خصوصیات واضح ہوتی ہیں:
(۱) حجۃ الوداع سے صرف چند ماہ قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات تحریری صورت میں جاری فرمائی تھیں، اس لحاظ سے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تحریری ہدایات ہیں۔
(۲) یہ انتہائی مستند ہیں۔ تحریر اور زبانی سند کے لحاظ سے یہ قطعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ ہدایات ہیں جن کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
(۳) خوش قسمتی سے ہم کو یہ ہدایات ایک سندھی محدث امام ابو جعفر دیبلی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں۔
(۴) ان ہدایات سے واضح ہوتا ہے کہ کسی حاکم کی نگاہ میں کن امور کا اولیت حاصل ہونی چاہیئے اور حاکم کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان من اللہ و رسولہ ’’یا ایھا الذین امنوا اوفوا بالعقود‘‘۔
’’اللہ کے نام سے جو رحمٰن اور رحیم ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، عہد و پیمان کو پورا کرو‘‘ (القرآن)
عہد من عند النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) لعمرو ابن حزم الانصاری حین بعثہ الی الیمن۔
’’عمرو بن حزم انصاری کو یمن بھیجنے کے موقع پر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے یہ ہدایات عمرو ابنِ حزم کو دی جا رہی ہیں۔‘‘
(۱) امرہ بتقوی اللہ فی امرہ کلہ ’’ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون‘‘۔
’’وہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ (عمرو ابن حزم) اپنے تمام معاملات و نظام میں اللہ سے ڈرتا رہے کیونکہ: اللہ ان کے ساتھ ہے جو (اس سے) ڈریں اور جو خوبی کے ساتھ اپنے کام انجام دیں‘‘ (القرآن)
(۲) وامرہ ان یاخذ الحق کما امرہ اللہ۔
’’وہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ (حکومت کے) واجبات اسی طرح وصول کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔‘‘
(۳) وان یبشر الناس بالخیر ویامرھم بہ۔
’’لوگوں میں بھلائی کی تلقین کرے اور اسی کا حکم دے۔‘‘
(۴) ویعلم الناس القراٰن ویفقھم فیہ۔
’’لوگوں کو قرآن سکھائے اور قرآن کی سمجھ پیدا کرے۔‘‘
(۵) وینھٰی الناس ان لا یمس احد القراٰن الا وھو طاھر۔
’’اور لوگوں کو اس بات سے منع کرے کہ کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگائے۔‘‘
(۶) ویخبر الناس بالذی لھم والذی علیھم۔
’’اور لوگوں کو (صاف طور پر) باخبر کر دے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں۔‘‘
(۷) ویلین للناس فی الحق، ویشتد علیھم فی الظلم، وان اللہ کرہ الظلم و نھٰی عنہ فقال: ’’الا لعنۃ اللہ علی الظالمین‘‘۔
’’لوگوں کے حقوق دینے میں نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ (البتہ) اگر کوئی ظلم کرے تو اس پر سختی کرے۔ اللہ نے ظلم کو ناپسند فرمایا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے: سنو! ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔‘‘
(۸) ویبشر الناس بالجنۃ وبعملھا۔
’’لوگوں میں جنت اور جنت دلانے والے اعمال کی تبلیغ کرے۔‘‘
(۹) وینذر الناس بالنار و بعملھا۔
’’اور لوگوں کو جہنم اور جہنم والے اعمال سے ڈرائے۔‘‘
(۱۰) ویستألف الناس حتیٰ یفقھوا فی الدین۔
’’اور لوگوں کی دلداری کرے تاکہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں۔‘‘
(۱۱) ویعلم الناس معالم الحج و سننہ و فرائضہ و ما امر اللہ بہ والحج الاکبر والحج الاصغر (وھو العمرۃ)۔
’’اور وہ لوگوں کو حج کے مناسک، اس کے طریقے اور اس کے فرائض سکھائے اور اللہ کے احکام کی تعلیم دے اور حجِ اکبر اور حجِ اصغر (عمرہ) سکھائے۔
(۱۲) وینھٰی الناس ان یصلی احد فی ثوب واحد الا ان یکون ثوبًا واحدًا یثنی طرفیہ علی عائقیہ۔
’’لوگوں کو اس بات سے منع کرے کہ وہ ایک چھوٹے سے کپڑے میں نماز ادا کریں، البتہ اگر کپڑا بڑا ہو اور اس کے دونوں کنارے دونوں شانوں پر ڈال لیے جائیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔‘‘
(۱۳) وینھٰی ان یجتبی احد فی ثوب واحد فضی بفرجہ الی السماء۔
’’(نماز میں) کوئی شخص ایک کپڑا پہن کر اس طرح اکڑوں نہ بیٹھے کہ اس کی ستر کھلی ہوئی ہو۔‘‘
(۱۴) ولا یعقص احد شعر راسہ اذا اعضاء علی قضاء۔
’’اگر کسی نے اپنے بال بڑھا کر گدی پر لٹکا لیے ہوں تو ان کا (نماز میں) جوڑا نہ باندھے۔‘‘
(۱۵) وینھٰی اذا کان بین الناس صلح عن الدعا الی القبائل والعشائر و لیکن دعاءھم الی اللہ وحدہ لا شریک لہ فمن لم یدع الی اللہ و دعا الی العشائر و القبائل فلیعطفوا بالسیف حتی یکون دعاءھم الی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
’’اور لوگوں کے درمیان اگر (اختلاف ختم کرنے کے لیے) صلح ہو رہی ہو تو لوگوں کو اس بات سے منع کرو کہ وہ (اپنے اپنے) قبیلہ یا (اپنے اپنے) خاندان کا نعرہ لگائیں۔ ان کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا نعرہ لگانا چاہیئے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا نعرہ نہ لگائیں اور خاندانوں اور قبیلوں کی طرف بلائیں تو ان کو تلوار کے ذریعے سے جھکایا جائے یہاں تک کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا نعرہ لگائیں۔‘‘
(۱۶) ویامر الناس باسباغ الوضوء وجوھھم وایدیھم الی المرافق وارجلھم الی الکعبین ویمسحوا برؤوسھم کما امر اللہ۔
’’اور وہ لوگوں کو حکم دے کہ وہ وضو میں اپنے چہروں کو اچھی طرح دھوئیں، ہاتھوں کی کہنیوں اور پیروں کے ٹخنوں تک پانی پہنچائیں، وہ اپنے سروں پر اس طرح مسح کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔‘‘
(۱۷) وامرہ بالصلوٰۃ لوقتھا واتمام الرکوع والخشوع ویفلس بالصبح ویھجر بالھاجرۃ حتٰی تمیل الشمس وصلوٰۃ العصر والشمس فی الارض مدبرۃ والمغرب حین یقبل اللیل ولا یؤخر حتٰی تبدو النجوم فی السماء والعشاء اول اللیل، وامرہ بالسعی الٰی الجمعۃ اذا نودی لھا، والغسل عند الرواح۔
’’اور انہوں نے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے) اس کو (عمرو ابن حزم کو) حکم دیا ہے کہ وہ نمازیں وقت پر ادا کرے، رکوع اور خشوع (قلبی جھکاؤ) کو مکمل کرے۔ نمازِ فجر اندھیرے میں ادا کرے، اور سورج کے مغرب کی جانب جھکنے سے قبل نمازِ ظہر ادا کرے، اور عصر کی نماز اس وقت ادا کرے جب دھوپ زمین سے واپس ہونا شروع ہو، اور رات کی آمد کے وقت مغرب ادا کرے اور مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے ظاہر ہو جائیں، اور نمازِ عشا رات کے پہلے حصہ میں ادا کرے، اور اس کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو نماز کے لیے لپک کر پہنچے اور نمازِ جمعہ کے لیے جاتے وقت غسل کرے۔‘‘
(۱۸) وامرہ ان یاخذ من الغانم خمس اللہ۔
’’اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ مالِ غنیمت میں سے اللہ کا مقرر کردہ خمس وصول کرے۔‘‘
(۱۹) وما کتب علی المؤمنین فی الصدقۃ من العقار۔ عشر ما سقٰی البعل و ما سقت السماء۔ وعلٰی ما سقٰی الغرب نصف العشر۔ وفی کل عشر من الابل مثلتان و فی کل عشرین من الابل اربع شیاہ۔ وفی کل اربعین من البقر بقرۃ۔ وفی کل ثلاثین من البقر جذع او جذعۃ۔ وفی کل اربعین من الغنم سائمۃ شاۃ۔ فانھا فریضۃ اللہ التی افترض علی المؤمنین فی الصدقۃ فمن زاد خیرًا فھو خیر لہ۔
’’اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فرض کیا ہے اسے وصول کرے جس کی تفصیل اس طرح ہے: جس زمین کو دریا یا بارش نے سیراب کیا ہو اس کی پیداوار کا دسواں حصہ۔ اور جس کو ڈول (مصنوعی آبپاشی) سے سیراب کیا گیا ہو اس کی پیداوار کا بیسواں حصہ۔ ہر دس اونٹوں پر دو بکریاں اور ہر بیس اونٹوں پر چار بکریاں۔ اور ہر چالیس گائیوں پر ایک گائے۔ اور ہر تیس گائیوں پر ایک نر یا مادہ ایک سالہ بچہ۔ اور ہر چالیس چرنے والی بھیڑوں پر ایک بکری۔ زکوٰۃ کے سلسلہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر نافذ کیا ہے، جو شخص اس سے زیادہ دے تو وہ خود اس کے لیے بہتر ہے۔‘‘
(۲۰) وانہ من اسلم من یھودی او نصرانی اسلامًا خالصًا فانہ من المؤمنین لہ مثل ما لھم و علیہ ما علیھم۔ و من کان علٰی نصرانیتہ او یھودیتہ فانہ لا یفتنن علیھا۔
وعلٰی کل ما لم ذکر او انثٰی حرا و عبد دینار ران او عرضہ ثیابًا۔ فمن ادی ذٰلک فان لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ و من منع ذٰلک فانہ عدو للہ و رسولہ وللمومنین جمیعًا۔
’’یہ کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی مخلصانہ طور پر مسلمان ہو جائے اور دینِ اسلام اختیار کر لے تو وہ مومنوں میں سے ہو گا۔ اس کے وہی حقوق ہوں گے جو اہلِ ایمان کے ہوتے ہیں اور اس کے فرائض بھی انہی جیسے ہوں گے۔ اور جو اپنی نصرانیت یا یہودیت پر قائم رہے تو اس کو اس کے دین سے پھیرنے کے لیے سختیوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔
اور ہر بالغ مرد یا عورت آزاد یا غلام سے ایک پورا دینار یا اس کی قیمت کے مساوی کپڑے بطور جزیہ وصول کیے جائیں گے۔ جو شخص یہ (جزیہ) ادا کر دے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو گا، اور جو اس کو دینے سے انکار کرے گا تو وہ اللہ، اس کے رسول اور مومنین سب کا دشمن سمجھا جائے گا۔‘‘
توریت و انجیل وغیرہ کو کیوں پڑھنا چاہیئے؟
سید ناصر الدین محمد ابو المنصورؒ
امام محمد اسماعیلؒ بخاری نے تحریف کی تفسیر یوں کی ہے کہ تحریف کے معنی ہیں بگاڑ دینے کے اور کوئی شخص نہیں ہے جو بگاڑے اللہ کی کتابوں سے لفظ کسی کتاب کا مگر یہودی اور عیسائی خدا کی کتاب کو اس کے اصلی اور سچے معنوں سے پھیر کر تحریف کرتے تھے، انتہٰی۔ یہ قول اخیر صحیح بخاری میں ہے۔
شاہ ولی اللہ صاحبؒ اپنی کتاب فوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ اہلِ کتاب توریت اور کتبِ مقدسہ کے ترجمہ میں (یعنی تفسیر میں) تحریف کرتے تھے نہ کہ اصل توریت میں اور یہ قول ابن عباس کا ہے، انتہٰی۔
امام فخر الدین رازیؒ اپنی تفسیر کبیر میں سورہ مائدہ آیت ۱۴ کی تفسیر کرتے ہیں کہ تحریف سے یا تو غلط تاویل مراد ہے یا لفظ کا بدلنا مراد ہے اور ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ پہلی مراد بہتر ہے کیونکہ جو کتاب بار بار نقل ہو چکی اس میں تغیر لفظ کا نہیں ہو سکتا، انتہٰی۔
تفسیر درمنشور میں ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ توریت و انجیل جس طرح کہ ان دونوں کو اللہ نے اتارا تھا اسی طرح ہیں ان میں کوئی حرف بدلا نہیں گیا لیکن یہودی بہکاتے تھے لوگوں کو معنوں کے بدلنے اور غلط تاویل کرنے سے جیسا کہ آج کل کے بعض مسلمان علماء و مشائخ جو قرآن کی ایک آیت کو پکڑ کر الگ الگ تاویل اپنے اپنے مطلب کے موافق کرتے ہیں اور آپس میں خوب جھگڑتے ہیں، اور حالانکہ کتابیں تھیں وہ جن کو انہوں نے اپنے آپ لکھا تھا اور کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے نہ تھیں، مگر جو اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں وہ محفوظ تھیں ان میں کچھ بدلنا نہیں ہوا تھا۔ انتہٰی۔ سورہ بقرہ رکوع ۹ میں جو یہ آیت ہے:
فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ یَکْتُبُوْنَ الْکِتَابَ بِاَیْدِیْھِمْ ثُمَّ یَقُوْلُوْنَ ھٰذَا مِنْ عِنْدِ اللہِ۔
’’پس افسوس اوپر حال ان لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔‘‘ ۔۔۔ انتہٰی۔
بیضاوی میں ہے:
ولعلہ اراد بہ ما کتبوہ من التاویلات الزانیۃ (شہادت قرآنی فصل ۷۲ ص ۱۰۲)
’’اور اس سے شاید وہ مراد ہے جو تاویلات یعنی تفسیریں انہوں نے (یعنی یہودیوں نے) سزائے زنا کی بابت لکھیں۔‘‘ انتہٰی۔
اس کے سوا ایسی کتاب کو محرف نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو سرے ہی سے جھوٹی کتاب ہے اسے تحریف سے کیا علاقہ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ علماء اسلام کا حسنِ عقیدت نسبت توریت و انجیل کی ہے ورنہ تحریف لفظی بلکہ اکثر آیتیں ان مقدس کتابوں میں ملائی جانا معتبر علماء اہل کتاب کے اقوال سے بصحت تمام ثابت ہے۔ باوجود اس کے مسلمانوں کو توریت و انجیل سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ اہلِ کتاب سے مناظرہ کر سکیں اور ان کتابوں کی عظمت سمجھنا تاکہ ایمان جاتا نہ رہے خاص کر اس واسطے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشر سے خبر دینے والے خدا پرستوں میں یہی کتابیں ہیں۔ اس کے سوا علماء اسلام اگر توریت وغیرہ کو محرف کہیں تو اس کا نصارٰی کب یقین کریں جب تک معتبر نصرانی علماء توریت و انجیل کی تحریف کا اقرار کریں۔ اس جگہ میں نے یہ سب قول مفسرین وغیرہ ان مسلمانوں کی ترغیب کے واسطے نقل کیے جو سمجھتے ہیں کہ توریت و انجیل کو آنکھ سے بھی نہ دیکھنا چاہیئے اگرچہ الف لیلٰی وغیرہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے نعوذ باللہ۔
اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنَاھُمُ الْکِتَابَ یَتْلُوْنَہٗ حَقَّ تِلَاوَتِہٖ اُولٰئِکَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ وَمَنْ یَکْفُرْ بِہٖ فَاُولٰئِکَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۔۔الخ (سورہ بقرہ رکوع ۱۴)
’’جو لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، پڑھتے ہیں اس کو، حق پڑھنے اس کے کا، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اس کے، پس یہ لوگ وہی ہیں زیاں پانے والے‘‘۔ انتہٰی
اب مثال کے لیے دو ایک مقام اور بیان کروں جس سے معلوم ہو گا کہ اہلِ اسلام کو یہود و نصارٰی اور دنیا کی سب قوموں سے بحث و مناظرہ کرنا مقتضائے حمیت اسلام ہے، بلکہ خدا ہی نے مسلمانوں کو مناظرہ کا طرز تعلیم کیا ہے کہ یہود و نصارٰی کے عقائد کی تردید اور ان کی کتابوں کے مضامین سکھلائے۔ چنانچہ قال اللہ تعالٰی جل شانہٗ:
اِنَّ ھٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاُوْلٰی صُحُفِ اِبْرَاھِیْمَ وَ مُوْسٰی۔
’’بالتحقیق یہ ہے پہلی کتابوں میں، کتابوں میں ابراہیم اور موسٰی کی۔‘‘
اب اگر کوئی توریت سے ناواقف ہو تو کیسے کہہ سکے کہ صحفِ ابراہیمؑ و موسٰیؑ میں یہی تعلیمیں نجات اور آخرت وغیرہ کی مرقوم ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ اس لیے اپنے دعوے کے اعتبار کی غرض سے مسلمانوں کو توریت و انجیل سے واقف ہونا چاہیئے۔
وَاِنَّہٗ لَتَنْزِیْلُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ o نَزَلَ بِہِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ o عَلٰی قَلْبِکَ لِتَکُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ o بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ o وَاِنَّہٗ لَفِیْ زُبُرُ الْاَوَّلِیْنَ o اَوَلَمْ یَکُنْ لَّھُمْ اٰیَۃً اَنْ یَّعْلَمَہٗ عُلَمَآءُ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ o
’’اور بالتحقیق یہ اترا ہے رب العالمین سے۔ اتارا روح الامین نے۔ اسے تیرے دل پر کہ تو بھی ایک ڈرانے والا ہو۔ صاف زبان عربی میں۔ اور بالتحقیق یہ ہے پہلوں کے صحیفوں میں۔ اور کیا ان کے واسطے یہ نشانی نہیں ہوئی کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں؟‘‘ (سورہ شعرا)
اب اگر پہلوں کے صحیفوں سے ہم واقف نہ ہوں تو کس طرح یہود و نصارٰی سے کہہ سکیں کہ یہ پہلوں کے صحیفوں میں ہے۔ اس کی تفسیر میں بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر یا اس کے معنے کتب متقدمین میں مرقوم ہیں، اور کتب کو تو سب جانتے ہیں کہ توریت و انجیل ہے۔ چنانچہ کشاف میں صاف لکھا ہے ’’کالتورات والانجیل‘‘ یعنی کتب سے مراد توریت و انجیل ہیں۔
اِنَّ الَّذِیْنَ یَکْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدٰی مِنْ بَّعْدِ مَا بَیَّنَّاہُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ اُولٰئِکَ یَلْعَنُھُمُ اللہُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّعِنُوْنَ۔
’’بالتحقیق جو لوگ چھپاتے ہیں ان صاف باتوں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کیں، بعد اس کے کہ ہم کتاب میں ظاہر کر چکے ان لوگوں کے واسطے، انہیں لعنت کرے گا اللہ اور لعنت کریں گے لعنت کرنے والے۔‘‘(سورہ بقرہ)
اس آیت کا شانِ نزول ابن اسحاق کی روایت سے سیرت ہشامی میں اس طرح پر ہے کہ معاذ بن جبل اور سعد بن معاذ اور خارجہ بن زید نے بعضے یہودی عالموں سے توریت کی کسی بات کا استفسار کیا لیکن یہود اس کو ان سے چھپا گئے اور بتلانے سے انکار کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو لوگ چھپاتے ہیں الخ۔ اور تفسیر حسینی میں ہے ’’ان الذین‘‘ علماء یہود جو بوجہ حسد ’’یکتمون‘‘ چھپاتے ہیں ’’ما انزلنا‘‘ جو ہم نے اتارا ’’من البینات‘‘ توریت میں واضح دلائل سے ’’والھدٰی‘‘ راہ دکھانا یعنی ہدایت ’’من بعد ما بیناہ‘‘ بعد اس کے کہ ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے طور پر بیان کیا ’’فی الکتاب‘‘ توریت میں یعنی ہم واضح کرتے ہیں اور یہ چھپاتے ہیں۔‘‘
دیکھیئے کہ مسلمانوں سے جو یہودیوں نے توریت کو چھپایا تو یہ بات خدا کو ایسی ناپسند معلوم ہوئی کہ اس شدت کے ساتھ ان پر لعنت کی۔ یہاں سے ظاہر ہے کہ خدا کو توریت سے مسلمانوں کو واقف کرنا کس قدر منظور تھا کہ اسے چھپانے کے سبب یہودیوں پر ایسی سخت لعنت فرمائی۔ اور پھر اسی سورۃ میں حق تعالٰی فرماتا ہے:
اِنَّ الَّذِیْنَ یَکْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللہُ مِنَ الْکِتَابِ۔
یہاں بھی یہودیوں کو وہی الزام دیا گیا ہے کہ انہوں نے غرض دنیاوی کے واسطے ان شہادتوں کو جو توریت میں دینِ اسلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تھیں ظاہر نہ کیا۔ پس اگر مسلمان توریت کے ان مضمونوں سے واقف ہو جاتے تو یہودیوں کے چھپانے سے پھر نقصان کیا تھا؟ مگر چونکہ اس زمانہ میں توریت عربی زبان میں ترجمہ نہ ہوئی تھی (دیکھو تواریخ ابو الفدا جو ساتویں صدی ہجری میں تھا) اس سبب سے ان باتوں کا اعلان صرف یہودیوں پر ہی منحصر تھا۔ اور جب کہ وہ ایسی باتوں کو چھپاتے تھے تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس حرکت سے سخت ناراض ہو کر فرمایا کہ
’’اُولٰئِکَ مَا یَأْکُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِھِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا یُکَلِّمُھُمُ اللہُ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ وَلَا یُزَکِّیْھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ o وَاِذْ اَخَذَ اللہُ مِیْثَاقَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّہٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُوْنَہٗ فَنَبَذُوْہُ وَرَآءَ ظُھُوْرِھِمْ ۔۔ الخ
’’یعنی وہ آگ کھاویں گے اپنے پیٹ میں اور خدا ان سے بات نہ کرے گا قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے ہو گا سخت عذاب۔ اور جب خدا نے اقرار لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ اس کو بیان کریں بنی آدم سے اور نہ چھپاویں، پس انہوں نے پھینک دیا وہ اقرار اپنی پیٹھ کے پیچھے۔‘‘ (آل عمران)
یہاں بھی وہی الزام ہے جو قرآن میں بار بار توریت وغیرہ کے مضامین چھپانے پر یہودیوں کو دیا گیا لیکن اگر توریت کے مضامین اس وقت میں مسلمانوں میں مشتہر ہو گئے ہوتے تو پھر یہودیوں کے چھپانے کی شکایت کیا تھی اور اسلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور کسی تدبیر کی حاجت کیا ہوتی؟ کیونکہ حضرت موسٰی نے توریت میں بنی اسرائیل سے صاف فرمایا تھا کہ ایک نبی میری مانند ہو گا، تم اس کی سننا۔ لیکن اب وہ دن آیا ہے کہ کتابوں کی کثرت اور ہر زبان میں توریت کا ترجمہ ہو جانے کے سبب اسلام کی فضیلت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر توریت و انجیل سے ایسی صاف اور واضح بیان ہوتی ہے جو اس سے پیشتر کبھی نہ ہوئی تھی۔ غرض اسی طرح الزام توریت چھپانے کی بابت یہودیوں کو بار بار بار دیا گیا ہے۔ دیکھو سورہ انعام وغیرہ۔
وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُّسُلِنَا۔
’’یعنی پوچھ ان رسولوں سے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا۔‘‘ (زخرف)
پوچھ ان رسولوں سے یعنی ان کی امت سے۔ بیضاوی میں لکھا ہے ان کی امت اور ان کے علماء دین سے۔ اور کشاف میں ہے کہ یہود و نصارٰی کی امت سے۔ اب خیال کیجئے کہ ان سے پوچھنا ازروئے توریت و انجیل ہی تھا یا کچھ ان کی بنائی ہوئی باتوں سے غرض تھی؟
فَاِنْ کُنْتَ فِیْ شَکٍّ مما انزلنا الیک فاسئل الذین یقرؤن الکتاب من قبلک۔
’’یعنی پس اگر تو ہے شک میں اس سے جو اتارا ہے ہم نے تیری طرف تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے والی۔‘‘ (سورہ یونس)
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی محض تھے، کوئی کتاب نہ پڑھ سکتے تھے، اور اگر پڑھ سکتے تو توریت عربی زبان میں نہ تھی بلکہ عبرانی میں تھی۔ اس سبب سے حکم ہوا کہ پوچھ ان سے۔ اور جو شخص آپ توریت پڑھ سکتا ہو تو پوچھنے کی نسبت یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ توریت میں دیکھ لے۔ مگر اب جو لوگ کہ ان آیتوں سے تو انکار نہیں کر سکتے مگر توریت کے پڑھنے سے گبھراتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ خط کو تو نہیں کھولتے صرف قاصد سے زبانی خبر پوچھتے ہیں۔ یعنی بڑی تسلی کو چھوڑ کر ادنٰی تسلی کی طرف دوڑتے ہیں۔
وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسٰی تِسْعَ اٰیَاتٍ بَیِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ۔
’’یعنی اور بالتحقیق ہم نے موسٰی کو نو نشانیاں صاف دیں پس پوچھ بنی اسرائیل سے۔‘‘
اب دیکھئے کہ ان نشانیوں کا ذکر توریت میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی توریت سے خوب واقف نہ ہو تو کیونکر یہ نو گنوا سکے کیونکہ قرآن مجید میں اسرائیلی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، پس ضرور ہے کہ انہیں کتابوں سے ثابت کیا جائے۔ پوچھ بنی اسرائیل سے یعنی توریت کے پڑھنے والوں سے، ورنہ ان کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسٰیؑ انہیں لوگوں کے درمیان تھے پس انہیں کی کتابوں سے اس کا ثبوت بہت مستحسن ہے اور یہاں بھی یہی بات ہے کہ پوچھ اہلِ کتاب سے۔ اسی طرح سورہ نحل میں ہے:
فَاسْئَلُوْا اَھْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔
’’پس پوچھ اہل ذکر (یعنی اہل کتبِ الٰہی) سے اگر نہیں جانتے ہو۔‘‘
اور اسی طرح سورہ انبیاء رکوع ۱ میں ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔
اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ اُوْتُوْا نَصِیْبًا مِّنَ الْکِتَابِ یُدْعُوْنَ اِلٰی کِتَابِ اللہِ لِیَحْکُمَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ یَتَوَلّٰی فَرِیْقٌ مِّنْھُمْ وَھُمْ مُعْرِضُوْنَ۔
’’یعنی کیا تو نے نہیں دیکھے وہ لوگ جن کو ملا ہے حصہ کتاب میں سے، وہ بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، پھر الٹے پھرے ایک فریق ہٹ کر اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔‘‘
تفسیر حسینی میں ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک گروہ کو اسلام کی دعوت دی۔ نعمان بن ابی اوفی نے کہا میں آپ کے ساتھ اپنے علماء دین کی موجودگی میں مناظرہ کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیفہ توریت سے لایا جائے جو کہ میری صفت اور نعت پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اس سے انکار کیا اور وہ آیات نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ توریت پڑھتے ہیں پھر منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ جو رؤسا ہیں اور یہ حق سے اعراض کرتے ہیں، انتہٰی۔ یہاں سے مناظرہ کا قانون صحیح دانشمندوں کو معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مناظرہ کے وقت قرآن مجید پیش نہیں کیا کیونکہ وہ اسے نہیں مانتے تھے بلکہ انہیں کی کتاب منگوائی۔ اب وہ لوگ جنہیں توریت و انجیل سے واقف کاری نہیں ہے کیونکر اپنے کسی دعوٰی کے ثبوت میں ایسی جرأت کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس سے بے پروا ہیں ثابت ہے کہ انہیں دینِ اسلام اور خدا اور رسولؐ کے نام کی حمایت سے بھی کچھ غرض نہیں ہے اور فعلِ رسول اللہؐ کو بھی پسند نہیں کرتے۔
(از نوید جاوید ص ۵۶ تا ۶۱)
علامہ عبد اللہ یوسف علی کی تفسیرِ قرآن کا ایک مطالعہ
محمد اسلم رانا
انگریزی میں ترجمہ و تفسیر قرآن مجید پر بہت تھوڑا کام ہوا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ پروفیسر علامہ عبد اللہ یوسف علی کے ترجمہ اور مختصر حواشی کا بڑا چرچا ہے۔ یورپی اور امریکی ممالک میں یہی تفسیر مقبول ہے۔ قریباً سبھی اشاعتی اور تبلیغی ادارے بشمولیت مسلم ورلڈ لیگ اسی کو چھاپتے اور شائع کرتے ہیں۔ اندریں حالات اس ترجمہ اور تفسیری حواشی کا مختصر سا مطالعہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔
قصہ ہاروت اور ماروت کا
بابل کے لوگ سحر اور جادوگری کے فن میں شدید دلچسپی لیتے تھے۔ جب ان علوم کا زور حد سے بڑھ گیا اور عوام کے اذہان میں ادیانِ حق، انبیاء کرام اور اولیاء صالحین کی حیثیت خلط ملط اور خراب ہو کر کاہنوں، ساحروں، عاملوں اور شعبدہ بازوں کی سطح پر گر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے ان دو علمبردار گروہوں کے درمیان نمایاں فصل و امتیاز کرانے اور اصلاحِ احوال کے لیے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو انسانی صورت و قالب میں بھیجا جو اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے فرشتے تھے، لیکن جب ایک غرض خاص کے ساتھ انسانوں کے درمیان رہنے بسنے کے لیے بھیجے گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی شکل و شبہات، رنگ و روپ اور جسم و قالب انسانوں ہی کا ہو گا۔ یہ انسان نما ملائکہ کسی پر بھی حقیقتِ سحر کو نہ کھولتے، کسی کو بھی کلماتِ سحر پر مطلع نہ کرتے جب تک اسے متنبہ نہ کر دیتے۔
ہوتا یہ تھا کہ فسق پیشہ اور بدکردار لوگ ہاروت اور ماروت کو گھیرتے اور ان سے اصرار کر کے دریافت کرتے کہ آپ ہمیں سحر سے تو روک رہے ہیں لیکن یہ تو بتائیے کہ سحر کہتے کسے ہیں؟ وہ ہیں کون سے اعمال جن پر سحر کا اطلاق ہوتا ہے؟ فرشتے انہیں تنبیہ و یاددہانی کے بعد کہ اس فن سے کام لینا کفر ہے، جب انہیں آگاہ و خبردار کرنے کے لیے ان اعمال و اقوال کی نقل و حکایت ان کے سامنے کرتے تو یہ فسق پیشہ لوگ اس سے یہ فائدہ اٹھاتے کہ خود اس فن ہی کے سیکھ جانے کا کام لینے لگتے۔ بالکل ایسی ہی بات جیسے آج کوئی کسی فقیہ عالم سے دریافت کرے کہ رشوت اور سود کا اطلاق کن کن آمدنیوں پر ہوتا ہے اور پھر ان سے بچنے کے بجائے الٹا انہیں طریقوں پر عمل شروع کر دے۔ (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ماجدی)
اس ضمن میں ایک اخباری مضمون یاد پڑا، جاپانی پولیس نے عوام کو چوروں کے ہتھکنڈوں سے آگاہ کرنے کے لیے ایک کتاب لکھ کر رکھ دی۔ ایک چور وہ کتاب پڑھ کر اس پر نوٹ لکھ گیا ’’شکریہ! مجھے چوری کرنے کا ایک طریقہ یہ کتاب پڑھ کر معلوم ہوا‘‘۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لوگوں کو جادوگری سے بچنے کے لیے اس کی حقیقت و ماہیت سے آگاہ کرنا تھا، وہ جادو سکھانے کی غرض سے نہیں بھیجے گئے تھے، ان کا جادو سیکھ جانا لوگوں کی اپنی بدکرداری تھی۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں:
’’ہاروت اور ماروت کو مجازًا فرشتے کہا گیا ہے، اس کے معنی ہیں علم، سائنس (یا حکمت) اور طاقت والے اچھے لوگ۔ جدید زبانوں میں اچھی اور خوبصورت عورت کو ’’فرشتہ‘‘ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات میں فرشتوں کو مؤنث بتایا جاتا تھا اور جو صفات میں نے بیان کی ہیں ان سے منسوب کی جاتی تھیں۔ جس سے مطلب اچھائی، علم، حکمت اور طاقت تھا۔ ان کا دور وہ زمانہ فرض کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی کتاب مدراش میں دو فرشتوں کی کہانی ہے جو حق تعالیٰ کی اجازت سے دنیا میں آئے لیکن ہوس کا شکار ہو گئے۔ بطور سزا بابل میں پاؤں باندھ کر لٹکا دیے گئے۔ ابتدائی عیسائیوں میں بھی گنہگار فرشتوں کا سزا پانا مانا جاتا تھا۔ ممکن ہے یہاں ایسی روایات کی طرف اشارہ ہو۔‘‘
اس موقع پر انہوں نے (حاشیہ نمبر ۱۰۴) بائبل سے جو دو حوالے دیے ہیں، حسبِ ذیل ہیں:
(۱) ’’کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔‘‘ (پطرس ۲: ۴)
(۲) ’’اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔‘‘ (یہوداہ کا عام خط ۱: ۶)
ہاروت اور ماروت کے قرآنی قصہ کے بارے میں علامہ صاحب کے مذکورہ خیالات خاصے گمراہ کن ہیں۔ ان کا مدراش اور بائبل کے مذکورہ حوالوں کی طرف انتساب علامہ صاحب کے علمی افلاس اور فکری تہی دامنی کی غماز ہے۔ نافرمانی قرآنی فرشتوں کا شیوہ نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو تو جو حکم ملے فقط اسی پر عمل کرتے ہیں (تحریم ۶)۔ فرشتوں کو عورتیں کہنا مشرکینِ عرب کا شیوہ تھا (زخرف ۱۹)۔
بائبل کی مشکوک پوزیشن
جس زمانہ میں علامہ صاحب نے تفسیر قرآن مجید لکھی، برصغیر میں انگریزی اقتدار عروج پر تھا۔ انگریزوں کے مذہب اور افکار و نظریات کی برتری کا دور دورہ تھا۔ بائبل سے متعلق اس کے اپنے پیروکاروں کے اعتقادات ڈانواڈول تھے۔ علمِ تنقید اور سائنسی علوم نے بائبل کے بیانات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ بائبل پر سے لوگوں کا اعتقاد اٹھ چکا تھا۔ حتٰی کہ حضرت ابراہیمؑ، موسٰیؑ اور عیسٰیؑ محض فرضی اور تخیلاتی ہستیاں شمار کیے جانے لگے تھے۔ پادری منیلی لکھتے ہیں:
’’بعض مصنفین کا خیال تھا کہ بزرگانِ اسرائیل اور ان کے آباؤ اجداد کی کہانی من گھڑت افسانہ ہے اور ابراہیم محض خیالی ہستی ہے۔‘‘ (ہماری کتب مقدسہ ۔ مصنفہ پادری جی ٹی منیلی ایم اے۔ ترجمہ پروفیسر جے ایس امام الدین، مسز کے ایل ناصر ۔ مطبوعہ ۱۹۸۱ء ص ۱۱۷)
ڈاکٹر گور رقم طراز ہیں:
’’ہمارا ایمان بائبل میں اس درجہ بڑھ گیا کہ ہم ماننے لگے کہ اس کا ہر ایک بیان صحیح ہے۔ ان ایام میں اس ایمان کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سائنس نے ناممکن کر دیا ہے کہ ہم مانیں کہ دنیا کی یا ہماری نسل کی بائبل کے بیان کے مطابق پیدائش ہوئی۔ صرف یہی نہیں کہ اسرائیلیوں کی مذہبی رسوم اور باتیں دوسری قوموں میں بھی پائی جانی معلوم ہو گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ پرانے عہد نامہ (عیسائی بائبل کے پہلے حصہ۔اسلم) کی تاریخی باتیں اب محض کہانیاں ثابت ہو گئی ہیں۔ بلکہ نکتہ چینی نے یہاں تک حملہ کر دیا ہے اور وہ یہاں تک نئے عہد نامہ (عیسائی بائبل کے دوسرے حصے۔اسلم) کی تحلیل کر رہی ہے کہ ہمارے نجات دینے والے (مسیح۔اسلم) کی شخصیت پر بھی شک کیا جا رہا ہے۔ یہ صاف ہے کہ پیدائش، باغ عدن، آدم کے گناہ کرنے اور طوفان (نوح۔ اسلم) کے بیان میں ہمیں سائنس کی صحت نہیں مل سکتی۔ یہ ویسی ہی کہانیاں ہیں جیسے کہ پرانے زمانے کے لوگ دنیا کی پیدائش کے بارے میں بنا لیا کرتے تھے اور اسرائیلی لوگوں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایسی کہانیاں بنائیں۔‘‘ (مسائل کلیسا ۔ مصنفہ ڈاکٹر گور ۔ ترجمہ مسٹر جے ڈی عنبر تحصیلدار ۔ مطبوعہ ۱۹۲۷ء ۔ صفحات ۹۵، ۱۰۶)
یہودی مفسر جے ایچ ہرٹز نے لکھا:
’’ایک نسل پہلے تک بائبل کے نقاد کتاب پیدائش میں بزرگوں (ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ۔ اسلم) کی کہانیوں کو جھوٹ و جعل سازی کا پلندہ قرار دیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ انہیں روایات کہتے، پر مستند تاریخ کا درجہ دینے کو قطعاً تیار نہ تھے۔ ان بیانات کی معقول وضاحت کرنے سے بڑی بڑ اور کفر کوئی نہیں تھا۔ ایک نقاد نے ابراہیمؑ کو ’’لاشعور کی تخلیق‘‘ کہا، دوسرے نے بے جان پتھر پکارا، تیسرے نے ستاروں والے آسمان، اور چوتھے نے مقدس مقام قرار دیا۔‘‘ (یہودی تفسیر بائبل مطبوعہ ۔۔۔)
مسلم متاثرین
برصغیر (پاک و بھارت) میں مسلمانوں سے اقتدار چھن چکا تھا، انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی سب سے بڑی کوشش تحریک آزادیٔ ہند ۱۸۵۷ء ناکام ہو چکی تھی، مسلمان محکوم اور شکستہ دل تھے، ملّی محاذ پر کام کرنے والے اصحاب بھی فکری سطح پر انگریزوں سے متاثر و مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور قرآنِ حکیم کو بھی اپنے آقاؤں کی بائبل کا سا خیال کرنے لگے۔ اس ضمن میں جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی نے خوب لکھا:
’’انیسویں صدی کے آغاز میں مغربی فلسفے کی سرسری معلومات کی بنیاد پر عالمِ اسلام کے بعض جدت پسند حضرات اسلامی عقائد میں سے ان تمام چیزوں کا انکار کر بیٹھے تھے جنہیں مغرب کے لوگ توہم پرستی کا طعنہ دیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے قرآن مجید میں ایسی ایسی تحریفات کی ہیں جنہیں دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے، اور اس غرض کے لیے قرآن کریم کی تقریباً آدھی آیات کو مجاز، استعارہ اور تمثیل قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں دسیوں مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کے آگے فرشتوں کے سجدہ ریز ہونے اور ابلیس کے انکار کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن چونکہ مغرب میں ڈارون کا نظریۂ ارتقا اس دور میں کافی مقبول ہو رہا تھا اور اس کی کچھ ناتمام سی اطلاعات ہندوستان میں بھی پہنچ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے یہ دعوٰی کر دیا کہ قرآنِ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں اور ابلیس کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ محض ایک تمثیل ہے اور آدم علیہ السلام کا کوئی شخصی وجود ہے نہ فرشتوں کا اور نہ ابلیس کا۔ چنانچہ سرسید احمد خان لکھتے ہیں: ’’آدم کے لفظ سے وہ ذاتِ خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملّا باوا آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوعِ انسانی مراد ہے‘‘ وغیرہ وغیرہ۔‘‘ (علوم القرآن ۔ مصنفہ مولانا محمد تقی عثمانی ۔ مطبوعہ ۱۴۰۸ھ ص ۴۰۲)
مولانا صاحب مزید رقم طراز ہیں:
’’سرسید اور ان کے ہم نواؤں نے پورے قرآن کو شاعرانہ تمثیلات کا مجموعہ بنا کر رکھ دیا۔‘‘ (ایضاً ص ۳۷۸)
راقم الحروف کو مرزا غلام احمد قادیانی کا کوئی مطالعہ نہیں ہے البتہ ان کے ایک دستِ راست محمد علی لاہوری کی تفسیر ’’بیان القرآن‘‘ دیکھنے کا موقع ملا ہے جو مجاز تمثیل، تشبیہ، استعارہ، روحانیت، مراد، مطلب، یعنی کی اصطلاحات کے گرد گھوم کے رہ گئی ہے۔ علامہ عبد اللہ یوسف علی بھی اسی دور کی پیداوار تھے، بائبل کے مندرجات کے حشر سے واقف تھے، زمانہ کی ہوا، فضا اور اپنے پیشروؤں سے ضرور متاثر تھے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ العیاذ باللہ۔
عیسائیت سے متاثر
(۱) سورۃ بقرہ آیت ۶۳ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوہِ طور پر حضرت موسٰیؑ کو دس احکام اور شریعت دی گئی تھی۔
واضح ہو کہ یہودی (اور عیسائی) عقیدہ کے مطابق آپؑ کو دو تختیاں ملی تھیں، ان پر دس احکام لکھے ہوئے تھے (خروج ب ۲۰) باقی شریعت آپؑ کو منہ زبانی بتائی جاتی تھی (خروج ب ۲۵) اور آپؑ وہ احکام آ کر قوم کو سناتے تھے (خروج ب ۲۵) اور لکھتے تھے (استثنا ۳۱: ۲۴)۔ مسلمانوں کے ہاں دس احکام اور شریعت کا جدا جدا نظریہ نہیں ہے۔ تختیاں کافی تھیں، لفظ ’’اَلْواح‘‘ (جمع کسر اَلْ کے ساتھ) آیا ہے، ان پر مکمل شریعت لکھی ہوئی تھی، تورات وہی تختیاں تھیں۔ علامہ صاحب کا بحیثیت مسلمان یہودی نظریہ بیان کرنا سخت غلطی ہے۔
(۲) عیسائیوں کے ہاں قاعدہ ہے کہ سن عیسوی کو انگریزی میں AD لکھ دیتے ہیں جو لاطینی اصطلاح Anno Domini کا مخفف ہے۔ اس کے معنی ہیں In the year of our Lord یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سال میں۔ مثلاً ۴۰۰ء کو انگریزی میں 400AD لکھیں گے۔ یہودی سنِ عیسوی کو AD کی بجائے سیدھا CE یعنی Christian Era لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے علامہ صاحب سنِ عیسوی کو AD لکھ کر اپنے آپ کو یہودیوں سے بھی گیا گزرا ثابت کر گئے۔
(۳) عیسائی یسوع کو Jesus اور مسیح کو Christ لکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کا ان کی تقلید کرنا کھٹکتا ہے۔ Jesus کی بجائے Isa اور Christ کی جگہ سیدھا Majih لکھنا چاہیئے تھا۔
(۴) حاشیہ ۳۹۷۲ میں ’’خدا کی بادشاہت‘‘ Kingdom of God اور نوٹ ۵۷۲۸ میں بشارت اسلام Gospel of Islam خالصتاً عیسائی اصطلاحات ہیں۔
عربی دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے اور انگریزی بائیں سے دائیں۔ علامہ صاحب نے انگریزی کو ترجیح دی اور اس کی تقلید میں قرآنی متن بھی بائیں سے دائیں لکھتے گئے۔ ان کا یہ رویہ ایک عام آدمی کو بھی بری طرح کھٹکتا ہے۔
قادیانیت سے متاثر
(۱) سورۃ النساء آیت ۱۵۸ میں مسیحؑ کے خدا کی طرف اٹھائے جانے کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
’’اس آیت کی قطعی تفسیر میں اختلاف رائے ہے۔ الفاظ ہیں: یہودیوں نے مسیح کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ پاک نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا (رَفَعَ) ایک مکتبِ فکر One School کی رائے میں مسیح پر عام انسانی موت وارد نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ آج تک جسم کے ساتھ آسمان میں زندہ ہیں۔ دوسرے مکتبِ فکر کا کہنا ہے کہ آپؑ وفات پا گئے تھے (تَوَفَّیْتَنِیْ۔ المائدہ ۱۲۰) لیکن اس وقت نہیں جب آپ کو صلیب دیا جانا فرض کیا گیا تھا۔ آپؑ کے ’’خدا کی طرف اٹھائے جانے‘‘ کا مطلب ہے کہ یہودی نظریہ کے مطابق ایک مجرم کی حیثیت سے بدنام کیے جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو اپنے رسول کی حیثیت سے سرفراز فرمایا۔ اگلی آیت بھی دیکھیں یہی رَفَعَ کا لفظ سورۃ ۱۰۴ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مذکور ہے۔‘‘
اس موقع پر علامہ صاحب خاصے بہک گئے۔ ’’اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا‘‘ امت کا صحیح اجماعی عقیدہ ہے۔ اسے ایک مکتب فکر کی طرف منسوب کرنا اس عقیدہ اور اس کے ماننے والوں کی اہمیت کو گھٹانا ہے۔ علامہ صاحب ان الفاظ کو نوکِ قلم پر لاتے کترا گئے۔ اس کے مقابلہ میں مٹھی بھر قادیانیوں کو دوسرا مکتب فکر قرار دینا مبالغہ آرائی ہے۔ حق تعالیٰ حضرت مسیحؑ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں لاکھ نبوت و رسالت سے نوازے اسے کون روک سکتا ہے اور اس سے کسی دوسرے پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ معانی آیت کے ماحول اور منظر میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے (انہیں اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور) مسیحؑ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرتؑ کو نبوت وقتِ مذکور پر نہیں ملی تھی۔ آپ اس سے پہلے نبوت سے نوازے جا چکے تھے۔ یہ تو آپ کا آخری وقت تھا۔ آپؑ کی نبوت پر ہی تو جھگڑا چل رہا تھا۔ اس آخری وقت میں نبوت دیے جانے کا نظریہ مضحکہ خیز ہے۔ اگر پیشتر ازیں آپ ایک عام آدمی کی سی سادہ زندگی بسر کر رہے تھے تو یہودی آپؑ کی جان کے دشمن کیوں تھے؟
اگر علامہ صاحب نے ذکر کر دیا تھا تو قادیانی نظریہ پر تنقید ضروری تھی۔ موجودہ صورتِ حال علامہ صاحب کی پوزیشن کو مشکوک بناتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت ۱۲ (توفیتنی) اور سورہ الم نشرح ۴ کے حوالے دینے سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ علامہ صاحب کا اپنا میلان قادیانی عقیدہ کی طرف تھا۔ ایک معمولی قاری بھی سورہ الم نشرح آیت ۴ کا ترجمہ پڑھ کر فورًا اسے غیر متعلق قرار دے گا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا لکھا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلند کرنا نہیں۔
(۲) سورۃ بقرہ آیت ۶۵ اصحابِ سبت کے واقعہ میں مولوی محمد علی کا باقاعدہ نام لے کر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔
(۳) ان کے ہاں جِن کوئی باقاعدہ مخلوق نہیں ہیں۔ ’’روح‘‘ غیر مرئی یا مخفی قوت ہیں (حاشیہ ۹۲۹)۔ سورہ جِن (نوٹ ۵۷۲۸) میں اپنے استاد محمد علی کی پیروی (دیکھیں بیان القرآن تمہید سورہ الجن) میں جِن ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عرب میں اجنبی تھے۔
تمثیل کی تعریف
تمثیل ایک فرضی کہانی ہوتی ہے جس کی مدد سے کوئی اخلاقی سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ پادری ڈملو لکھتے ہیں:
’’ایک حکایت، افسانہ جو انسانی زندگی کے قوانین اور رسوم و روایات کے موافق ہوتا ہے اس کی مدد سے انسانوں کے فرائض یا خدا کی باتیں بالخصوص خدا کی بادشاہت کی ماہیت اور تاریخ مجازًا بیان کی جاتی ہے۔ (تفسیر بائبل ۔ مطبوعہ ۱۹۴۴ء)
قرآن میں تمثیلوں کا نظریہ
(۱) علامہ صاحب کے نزدیک قصۂ اصحابِ کہف ایک تمثیل تھی (کہف ۹)۔
(۲) ذوالقرنین کے بارے لکھتے ہیں ’’یہ کہانی تمثیل سمجھی جاتی ہے‘‘ (سورہ کہف ۸۳)
(۳) سورہ بقرہ آیت ۷۱ والے گائے کے قصہ کو تمثیل کہتے ہیں۔
(۴) سورہ یس کے دوسرے رکوع میں بیان کردہ واقعہ کو بھی تمثیل لکھتے ہیں۔
(۵) ’’میں کسی تمثیل سمجھی جانے والی کہانی جیسا کہ ذوالقرنین کا قصہ ہے بارے تاریخی یا جغرافیائی امور کا تعلق نہیں سمجھتا۔ درحقیقت قرآن مجید میں بیان کردہ تمام کہانیاں اور حکایات بطور تماثیل روحانی معنوں کے لیے ہیں۔ ان کی صحیح تاریخوں، شخصیات اور مقامات سے متعلق گرماگرم بحثیں اور بڑے بڑے دعاوی خارج از امکان ہیں‘‘ (ص ۷۶)۔
(۶) سورہ آل عمران آیت ۴۹ میں معجزاتِ مسیحؑ کی فہرست ہے۔ فاضل مفسر نے ایک ایک معجزہ کو خالصتاً قادیانی نظریہ روحانیت مجاز اور استعارہ کی نذر کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ روحانی مُردوں کو زندہ کرتے اور روحانی بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ یہ لکھتے وقت نہ سوچا کہ ایسے روحانی مُردوں اور بیماروں کو سبھی انبیاء کرام اور علماء و مبلغین آج تک زندہ کرتے اور شفا دیتے رہتے ہیں۔ مسیحؑ کے بارے اتنے دھڑلے سے بیان کرنے اور تخصیص کی کیا ضرورت تھی؟
قرآن مجموعۂ تماثیل نہیں ہے
قرآن کریم تاریخ اور دستان گوئی سے قطعی مختلف کتاب ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کردہ قصوں سے مقصود قارئین کو سبق سکھانا ہے۔ روحانی و اخلاقی نتائج اور اسباق مرتب کرنا ہے۔ عبرت آموزی اور بصیرت افروزی ہے۔ زمان و مکان اور تاریخی و جغرافیائی لوازمات کو بے جا طوالت اور غیر ضروری قرار دے کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان قصوں کا ان سے فی الواقع کوئی تعلق نہیں تھا۔
قرآن کریم کی مخاطب عرب میں بسنے والی تین جماعتیں مشرکین، یہودی اور عیسائی تھیں۔ ہر قرآنی واقعہ میں سے کسی نہ کسی قوم سے متعلق تھا جو اسے جانتی بوجھتی تھیں اور اس خاص واقعہ سے اس کی اصلاح مقصود تھی۔ اگر تاریخ میں (کسی وجہ سے) بعض واقعات کا تذکرہ یا تفصیل نہیں ملتی یا ہم بعض کہانیوں کا تاریخی اور جغرافیائی اقدار سے موزوں تعلق نہیں پا سکتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ کہانیاں محض فرضی داستانیں تھیں، تمثیلیں تھیں۔ واضح رہے کہ قرآن ٹھوس زندہ حقائق پر مشتمل کتاب ہے۔ اگر یہ واقعات سچ مچ ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے تو انہیں کون اہمیت دے گا۔ ان سے سبق سیکھنے کی طرف کون مائل ہو گا۔ ان کہانیوں سے مراد صحابۂ کرام کی ڈھارس بندھانا، انہیں حوصلہ دلانا، ان کے ایمان مضبوط بنانا اور نصرتِ خداوندی کی امیدوں پر کھڑا کرنا تھا۔ ایسے میں وہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن خود تو ہوائی فائر کر رہا ہے جب کہ ہم زندہ سلامت اور صحیح آلام و مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ تپتی ریت، گرم پتھروں اور دہکتے کوئلوں پر لٹائے جاتے ہیں، دھوئیں کے عذاب، مارکٹائی، قتل، ہجرت، اعزہ و اقارب سے دوری، بھوک پیاس اور قید و بند کی سزائیں بھگتنی پڑ رہی ہیں۔
یہ حالات قرآنی قصوں کو بے وقعت بناتے، قرآن حکیم کی اہمیت گھٹاتے، قرآنی فرمودات و تعلیمات پر سے مسلمانوں کا اعتماد اٹھواتے، اسلام قبول کرنے والوں کی دل شکنی کرتے، اور اشاعتِ اسلام میں رکاوٹ بنتے، جس کا لازمی نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی کی صورت میں نکلتا۔ جبکہ صورتِ حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ تمام دکھوں اور مصیبتوں کی یلغار کے باوجود مسلمان ایمان کی مضبوطی اور تعداد میں بڑھتے ہی بڑھتے گئے جس کا صاف مطلب ہے کہ نزولِ قرآن کے دنوں قصص قرآن محض بچگانہ لوریاں، چکنی چپڑی باتیں، حسین داستانیں اور مقدس افسانے (Pious Fictions) (کاتب سے عبارت رہ گئی) سچے اور حقیقی فی الواقع ہو چکنے اور گوشت پوست کے انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے ٹھوس واقعات سمجھے جاتے تھے۔ ان سے شہہ پا کر مسلمان سختیوں اور تکلیفوں کو پرکاہ کے برابر بھی اہمیت نہ دیتے، نصرتِ الٰہی کے منتظر رہتے جو ہجرتِ مدینہ اور بالآخر فتح مکہ کی صورت میں آ کر رہی فللہ الحمد علیٰ ذالک۔
وہ قصے آج بھی اپنی اہمیت و افادیت کے اعتبار سے تروتازہ اور شگفتہ ہیں اور زمانہ نے ان کے مقاصد کو اجاگر کیا ہے اور ان کی بصیرت افروزی کو جِلا بخشی ہے، ان کی واقفیت پر مہرِ تصدیق ثبت کی ہے۔ اللہ کریم کو ایسے کوتاہ فہم اور پست ذہن لوگوں کی آمد کا پتہ تھا چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ قصص قرآن کی ضرورت و حکمت کے اشارات ملتے ہیں۔ صاف اور واشگاف الفاظ میں بتایا گیا کہ قرآن مجید میں پہلے گذر چکے لوگوں کے حالات بیان ہیں (نور ۳۴)۔ پہلی امتوں اور افراد کے قصے موضوع اور من گھڑت نہیں تھے، ان کی خبریں تھیں، حالات تھے (طہ ۹۹)۔ حضرات زکریاؑ، یحیٰیؑ، مسیحؑ اور مریمؑ کی باتوں کو غیب کی خبریں بتایا (آل عمران ۴۴)۔ نوحؑ کا قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی قوم جانتی نہیں تھی۔ یہ غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئیں کہ انجام متقیوں کے لیے ہے، نہ ڈرنے والے برباد کیے جائیں گے، ڈرنے والوں کو (بعد از تکلیف) نعمتیں ملیں گی (ہود ۴۹)۔ سابقہ رسولوں اور ان کی امتوں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے (یوسف ۱۱۱)۔ قومِ لوطؑ کی بربادی میں اہلِ بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں (حجر ۷۵)۔ قرآن مجید میں ڈرانے کی باتیں مذکور ہیں تاکہ لوگ بری راہوں سے بچیں (طہ ۱۱۳)۔ گذشتہ انبیاء کرامؑ کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم (اور آپؐ کے ساتھیوںؓ) کے دل مضبوط بنانے کے لیے سنائے گئے (ہود ۱۲)۔ نزولِ قرآن کا مقصد ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے حق میں ہدایت اور بشارت بن جائے (نحل ۱۰۲)
ان بلند و بالا مقاصد کا تمثیلوں کی مدد سے حصول ناممکنات سے ہے۔ قرآنی قصص برحق ہیں۔ آب و گل کی اس دنیا میں جیتے جاگتے چلتے پھرتے تاریخی انسانوں کو سچ مچ پیش آئے تھے، ان سے درسِ عبرت صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان سے کماحقہٗ مستفید ہوتے تھے۔
فرض کرنا
علامہ صاحب نے پہلوں کی کوئی لت چھوڑی نہیں جس میں مبتلا نہ ہوئے ہوں۔
(۱) سورۃ بقرہ آیت ۳۰ پر فرشتوں سے متعلق لکھتے ہیں ’’ہم انہیں جذبہ یا جوش کے بغیر فرض کر سکتے ہیں ۔۔۔ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی خواہشات کچھ نہیں تھیں‘‘۔
(۲) ہاروت و ماروت کا دور بھی فرض کرنے کی فکر میں ہیں۔
(۳) انہیں فرض کرنے کا بڑا چسکہ تھا۔ سورہ اعراف آیت ۱۵۰ میں ہے کہ حضرت موسٰیؑ نے قوم کی بچھڑا پرستی دیکھ کر شدید غصہ کی حالت میں تختیاں ڈال دیں، وہ ٹوٹی نہیں تھیں، ثابت رہیں۔ غصہ اترنے پر آپؑ نے اٹھا لیں لیکن ازروئے بائبل وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں (خروج ۳۲: ۱۰)۔ اس موقع پر علامہ صاحب لکھتے ہیں ’’یہ فرض کرنا کہ اللہ پاک کے نبیؑ نے تختیاں توڑ دیں (کفر نہیں تو) ایک لحاظ سے خلافِ ادب ہے۔‘‘
قرآن مجید سے تختیوں کا ثابت رہنا ثابت ہے۔ بائبل میں واضح ہے کہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ تختیوں کا توڑنا فرض کرنے کی کوئی ضرورت، موقع محل اور حاجت ہی نہیں تھی۔
(۴) ’’بہت سے ممتاز مفسرین نے اس شہر کو انطاکیہ فرض کیا ہے‘‘ (سورہ یس ۱۳)۔ حالانکہ فرض کسی نے بھی نہیں کیا، سبھی مفسرین وہ بستی انطاکیہ ہی سمجھتے اور لکھتے ہیں، ان کی غلط فہمی علیحدہ سوال ہے۔
یاد رہے کہ ’’فرض کرنے‘‘ کی لت نے عیسائیت میں عروج پایا تھا۔
سکندر اعظم کی نبوت
نامور یونانی فاتح سکندر اعظم بت پرست تھا، ارسطو کا معتقد تھا، ایرانی بادشاہ داراگشتاسپ کی بیٹی سے شادی کی، دعوت میں کثرتِ شراب نوشی سے جاں بحق ہوا تھا۔ اسے خواہ مخواہ مسلمان ہی نہیں بہتیرا کچھ ثابت کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اس ضمن میں لکھ گئے ’’ایتھوپیا کی روایاتی کہانیاں سکندر اعظم کو ایک بڑا پیغمبر بیان کرتی ہیں‘‘ (ص ۷۶۰)۔
ایسی روایات ناقابلِ التفات ہیں، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ پادری منیلی لکھتے ہیں ’’سیاسی مذہب کی ایک صورت بادشاہوں کی پرستش تھی جو یونانی دنیا میں سکندر اعظم کے ساتھ وجود میں آئی۔ خطابات مثلاً فیض رساں اور نجات دہندہ جو اس کے جانشینوں کو دیے گئے ۔۔۔۔ اگوستس کی پوجا دیوتا کے طور پر کی جاتی تھی۔ روم اور لاطینی مغرب میں بادشاہ یکے بعد دیگرے مرنے کے بعد دیوتاؤں کی فہرست میں شمار کیے گئے۔‘‘ (ایضاً ص ۳۸۹)
سکندر اعظم کو سورہ کہف کا ذوالقرنین ثابت کرنا آخر اتنا ضروری کیا ہے؟ بس اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ کوئی مسلمان بادشاہ تھا۔ قرآن کریم کے مخاطب جانتے تھے۔ ہم نہیں جان سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔
سادہ ترجمہ
علامہ صاحب کا ترجمہ قرآن بھی کوئی قابلِ تعریف کوشش معلوم نہیں ہوتی۔ معاف فرمائیں ہمیں تو بعض مقامات پر پروفیسر صاحب کے مقابلہ میں پادری جے ایم راڈویل ایم اے کا ترجمہ اچھا لگا۔ دو مثالیں بغرضِ ملاحظہ درج ذیل ہیں:
(۱) سورۃ رعد آیت اول
’’یہ کتاب (عظیم) کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لاتے‘‘ (تفسیر ماجدی)
علامہ صاحب:
These signs (or verses) of the Book that which hath been revealed onto thy from the Lord is the truth; but most men believe not.
راڈویل:
These are the signs of the Book! and that which hath been sent down to thee from they Lord is the very truth; but the most men will not believe.
(۲) سورۃ مریم آیت ۳
’’(قابلِ ذکر ہے) وہ وقت جب انہوں نے اپنے پروردگار کو خفیہ طور پر پکارا‘‘ (تفسیر ماجدی)
علامہ صاحب:
Behold! He cried to his Lord in secret.
راڈویل:
When he called upon his Lord with secret calling.
دردمندانہ مشورہ
القصہ زیر مطالعہ تفسیر خاصی گمراہ کن ہے، اس کی عام اشاعت نقصان دہ ہے، لہٰذا تبلیغی اداروں اور قرآن کریم کے ناشرین کرام کی خدمت میں دردمندانہ مشورہ ہے کہ وہ علامہ عبد اللہ یوسف کے ترجمہ و تفسیر قرآن کی بجائے مولانا عبد الماجد دریابادی کے انگریزی ترجمہ و تفسیر کی اشاعت فرمائیں۔ اس تفسیر کی غلطیوں کی نشاندہی ہمارے ایک فاضل دوست سید شیر محمد (گلبرگ لاہور) نے کر دی ہے۔ راقم الحروف کا حصہ ڈالنا ابھی باقی ہے۔ دبیدہ التوفیق۔ مولانا نے عام مسائل اور بالخصوص مذاہبِ عالم کے حوالہ سے جتنا مطالعہ پیش کر دیا ہے، مستقبل کے کسی مفسر سے اس کی قطعی توقع نہیں ہے۔ علم و فضل اٹھتا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں اس بیش بہا علمی خزینہ کی حفاظت اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔
قرآنی آیات کو مسخ کرنے کی گھناؤنی حرکت
ادارہ
ایک منظم سازش کے تحت جس طرح مسلمانوں کو ہدفِ ملامت بنایا جا رہا ہے اور مذہبِ اسلام میں طرح طرح کے کیڑے نکالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان شر پسندوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ جہاں ایک طرف اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھا جائے وہیں دوسری طرف مسلمانوں میں مذہب اسلام سے ایک قسم کی بدظنی پیدا کی جائے اور اشتعال انگیزی پیدا کر کے اپنا الّو سیدھا کیا جائے۔ ابھی حال ہی میں پندرہ روزہ ہندی جریدہ ’’سرتیا‘‘ مئی ۱۹۹۰ء (دوئم) میں سراج الحق نے اپنے مضمون ’’سعودی عرب میں ناری کی دردشا‘‘ میں جس طرح قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر گھناؤنے انداز سے پیش کرنے کی مذموم حرکت کی ہے اس سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ہندی جریدہ ’’سرتیا‘‘ نے یہ مضمون ایک سازش کے تحت شائع کیا ہے۔
آج دشمنانِ اسلام نے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے اور اسلام کے بارے میں لغویات بکنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ انہوں نے اپنی اس گھناؤنی سازش میں ایسے نام نہاد مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو سرِعام ننگے ہو کر شہرت حاصل کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ مذہب اسلام سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ مالی فائدے اور جھوٹی شہرت کے بھوکے ایسے لوگ دراصل دشمنانِ اسلام کے آلہ کار ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں جیسا نام رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں بھوپال کے مقبول واجد نے اپنے ایک مضمون میں توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ منکرِ خدا سراج الحق نے جس طرح کھلم کھلا مقدس قرآن پر حملہ کر کے اس کے غلط معنی پہنائے ہیں اور اہلِ اسلام پر بھی تہمتیں عائد کی ہیں وہ عالمِ اسلام کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ہندی جریدے سرتیا نے یہ مضمون شائع کیا تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا سکے۔ اس سازش میں سلمان رشدی کا پیروکار سراج الحق بھی شامل ہے جو نام کے اعتبار سے مسلمان ضرور لگتا ہے لیکن خود کو اس نے دائرہ اسلام سے الگ کر لیا ہے جیسا کہ اس نے مضمون کے شروع میں تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے:
’’میں خود ایک مذہبی مسلمان تھا اور سبھی مذہبی امور عقیدت سے انجام دیتا تھا لیکن مسلمانوں کی جائے پیدائش اور مسلم برادری کے لیڈر سعودی عرب کی حالت دیکھ کر اسلام سے میری تمام عقیدت ختم ہو گئی۔‘‘
سراج الحق نے اپنے پورے مضمون میں سعودی عرب اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایسی تصویر پیش کی ہے جو اس کی گندی ذہنیت کی علامت ہے لیکن سب سے زیادہ قابلِ مذمت اور قابلِ اعتراض بات اس نے قرآنی آیات کو توڑ کر اور اپنی طرف سے من مانی ڈھنگ سے پیش کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کے اقتباسات میں کہی ہے۔ وہ کہتا ہے:
’’خاص طور پر باہر سے آئی ہوئی عورتوں کا جو جسمانی استحصال ہوتا ہے اس کی یہاں (سعودی عرب میں) بڑی گھناؤنی شکل ہے جو کوئی بھی مذہب سماج برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ استحصال ان کی ذہنیت بن چکا ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ قرآن کے ۲۳ ویں باب میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا اسے مرنے کے بعد جنت میں انتہائی دلکش اور کم عمر غلام ملیں گے۔ واضح رہے کہ ان ممالک میں کم عمر اور خوبصورت غلاموں سے غیر فطری جنسی فعل کا عورت سے صحبت سے زیادہ چلن ہے۔‘‘
’’اسی طرح جب ان کا مذہب ہی فطری اور غیر فطری دونوں تعلقات کو تسلیم کر رہا ہے تو ایسا کیوں نہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو نام نہاد جنت سے محروم ہو جائیں گے۔‘‘
شیطان رشدی کے چیلے سراج الحق نے جس طرح من گھڑت طریقے سے مقدس قرآن کی سورہ یس میں کم عمر غلام اور ان کی بدفعلی کا ذکر کیا ہے وہ اس کے گندے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، اس سورہ میں کسی غلام کا ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ سورہ یس میں جس جگہ اس نے اپنی غلط بیانی، بدکلامی کا ثبوت دیا ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو:
’’اور تم کو بھی بس ان کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اہلِ جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو وہ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ ان کو پروردگار کی جانب سے سلام فرمایا جائے گا۔‘‘
ہاں قرآن شریف کے ۲۷ ویں پارے میں غلمان کا ذکر اس طرح ضرور آیا ہے:
’’وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے۔‘‘
اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مذہب اسلام پر لگائے گئے الزام شرپسندی کے سوا اور کچھ نہیں ہے جو ایک خاص مقصد کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا سوال ہے اور معاشرے میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات ہے تو سنجیدہ قسم کے غیر مسلم تک بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا کیا وہ دوسرے مذاہب میں بھی نہیں ہے۔ رہا سوال کسی ملک کی فرسودہ رسم و رواج اور سراج الحق جیسے بدکردار لوگوں کی بداعمالیوں کا تو اس سے مذہب اسلام کا کیا تعلق، ہر شخص کا فعل ہی اسی تک محدود ہے اور وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔
ملک کی موجودہ صورتحال میں جب کہ چاروں طرف بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے، ایک خاص طبقہ کی یہی کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں اور مذہب اسلام کے بارے میں فتنہ انگیز قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کریں تاکہ وہ اصل مسائل کی طرف توجہ نہ دے پائے۔ کبھی قرآن میں تبدیلی کا فتنہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کبھی شیطان رشدی کی پذیرائی کی جاتی ہے، اور کبھی مسلم حکمرانوں کی تاریخ کے نام پر زہر گھولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان شرپسندوں میں بھیڑ کی کھال اوڑھے سراج الحق جیسے بھیڑیے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ نجی مفاد اور جھوٹی شہرت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کو تیار رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اور انتظامیہ اس معاملے کی صحیح جانچ کر کے قصور واروں کو گرفت میں لے اور حالات کو بد سے بدتر ہونے سے روکنے کے لیے جلدازجلد قدم اٹھائے ورنہ حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔
(ہفت روزہ ’’حرمت‘‘ اسلام آباد)
شعرِ جاہلی اور خیر القرون میں ارتقائے نعت
پروفیسر غلام رسول عدیم
شعر و شاعری عرب معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ قبائل و احزابِ عرب شاعر قبیلے کی آنکھ کا تارا، عزتِ نفس کا پاسبان اور غیرت کا نشان تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ آج جاہلی عرب کے بارے میں جو کچھ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں اس کا بیشتر حصہ انہی شعراء کے ملکۂ سخن کا مرہونِ منت ہے۔ بادیہ نشین عرب فطرت کے نہایت قریب تھے اس لیے ان کے اطوار و عادات میں فطری بے ساختہ پن بدرجۂ اتم موجود تھا۔ تکلف، تصنع اور مبالغہ آمیزی ان کی عادت کے خلاف تھی۔ بات میں کھرا پن ضرور مگر کھراپن لہجے کی صداقت ہوتا ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں انہیں حقیقت پسندانہ رویے کا مالک کہنا چاہیے۔
ان کے اصنافِ سخن کو آسانی کے لیے ہم بڑی بڑی پانچ قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: فخر، حماسہ، تشبیب، ہجا، مدیح۔
(۱) فخر
دنیا میں ہر قبائلی نظامِ فخر قبیلے کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ چنانچہ عرب بھی عصبیتِ جاہلی کے زیرِ اثر اپنے قبیلے کی برتری کا اظہار کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بارہا مفاخرت و معاظمت کے معرکے پیش ہوئے۔ کبھی اجتماعی کبھی انفرادی۔ جیسے ایک عرب شاعرہ خنساء نے اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل ہو جانے پر ایک میلے میں ’’انا اعظم العربِ مصیبۃ‘‘ (میں عرب میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ ہوں)، صدر اسلام میں غزوۂ بدر میں جب ہند بنت عتبہ کا باپ، چچا اور بھائی غازیانِ اسلام کے ہاتھوں قتل ہوئے تو وہ بازارِ عکاظ میں جا کر بولی ’’اقرنوا جملی بجمل الخنساء‘‘ (میرا اونٹ خنسا کے اونٹ کے قریب کر دو) چنانچہ ایسا کیا گیا، پھر اس نے مصیبتیں برداشت کرنے میں ایک دوسرے پر مفاخرت و مقارعت کی۔ اسلام کی آمد پر قبائلی عصبیت جاتی رہی اور مفاخرت کے ایسے واقعات کا خاتمہ ہو گیا۔
(۲) حماسہ
جاہلی شاعری کی دوسری سب سے اہم صفت حماسہ تھی۔ یہ لوگ بلاشبہ شجاعت و حماست کے کوہ گراں اور دلاوری کے پیکر تھے۔ عملاً بھی بہادری کے جوہر دکھاتے اور زبانِ شعر سے بھی اپنی جگرداری سے لوگوں کو مرعوب کرتے۔ مثلاً جب تغلب کے رئیس عمرو بن کلثوم کی ماں لیلٰی نے عمرو بن ہندوائی حیرہ کے ہاں احساس تحقیر کے پیشِ نظر ’’واذلّا یا لتغلب‘‘ (اے بنی تغلب مقام رسوائی ہے) کا بے باکانہ نعرہ بلند کیا تو ایک طرف تو عمرو بن کلثوم نے والیٔ حیرہ کو آنِ واحد میں قتل کر دیا، دوسری طرف وہ زوردار شعر پڑھے جو حماسہ کی نہایت شاندار مثال ہے ؎
ونشرب ان وردنا الماء صفوًا
’’قبیلے جانتے ہیں کہ ہم نے بغیر کسی فخر کے ان کے کنکر والے نالوں تک میں گنبد بنا ڈالے۔ ہم جو چاہیں حکم دیں، جہاں چاہیں اتر پڑیں، جب ہم کسی جگہ آئیں تو صاف چشموں سے متمتع ہوتے ہیں، ہمارے دشمن کو گدلا پانی پینا پڑتا ہے۔‘‘
(۳) تشبیب
تیسری اہم صفت اہلِ عرب کے ہاں تشبیب تھی۔ اس میں شرب و شباب کی کیف آور فضا سے لے کر مناظر فطرت کی رنگینیوں تک سارے مضامین آجاتے تھے۔ وہ سوسائٹی جہاں شراب پینا معیوب نہ تھا اور جہاں مناظر فطرت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ نظارہ دیتے تھے وہاں امراء القیس، مرقش الاکبر، عبد اللہ بن عجلان اور مسافر بن ابی عمرو جیسے رنگین مزاج اور غزل گو شعراء کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔
(۴) ھجاء
عرب شاعروں کے ہاں ان کی افتاد طبع اور مخصوص سماجی ماحول کی بنا پر ہجویہ شاعری خاص اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اپنے قبیلے کے دفاع میں دوسروں پر طعن کرتے مگر مگر معیارِ اخلاق کی گراوٹ کے بغیر۔ وہاں عبید زاکانی، بسحق شیرازی (فارسی)، اور جعفر زٹلی واٹل نارنولی (اردو) جیسے پھکڑباز اور لچرگو نہیں ملتے۔ ان کے ہاں محبت کی گرم گفتاری ہے تو لہجے کی صداقت کے ساتھ، اور عداوت کی جگر دوزی ہے تو بھی حقیقت پسندی کا دامن چھوٹے بغیر۔ قریط بن انیف اپنے قبیلہ کی بزدلی کی ہجو کرتے ہوئے کہتا ہے ؎
یجزون من ظلم اھل الظلم مغفرۃ
ومن اساءۃ اھل السوء احسانا
’’میرے قبیلے کے لوگ وہ ہیں جو ظالم کا بدلہ بخشش سے دیتے ہیں اور برے کی برائی کے بدلے اس پر احسان کرتے ہیں۔‘‘
سوا ھم من جمیع الناس انسانا
’’گویا کہ تیرے رب نے ان کے سوا مخلوق میں کسی کو اپنی خشیت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔‘‘
(۵) مدیح
یہی وہ صنفِ سخن ہے جس سے عرب کی وصفی شاعری کئی رنگوں میں ظہور پذیر ہوئی۔ کبھی قبیلے کی تعریف کی جاتی ہے، کبھی رؤسائے قبیلہ ممدوح بنتے، گھوڑے کی گرم رفتاری، تلوار کی کاٹ اور برق ریزی، اور ناقہ کی سرعتِ رفتار کو موضوعِ سخن بنایا جاتا۔ یہی نہیں حیوانات، منازل، اخلاق، وقائع سب کو مقامِ مدح میں رکھا گیا۔ اسی سے ایک صنفِ سخن پھوٹی جو بعد میں ایک مستقل صنف بن گئی اور وہ ہے مرثیہ۔ اس میں بڑے معرکے کی شاعری نے جنم لیا۔ خنساء کے مرثیے خاصے کی چیز ہیں۔ ایک اعرابیہ نے اپنے بیٹے کی موت پر کیسے بلند پایہ شعر کہے ہیں ؎
’’تیرے بعد (کوئی جیے کوئی مرے) مجھے تو تجھی سے رونق تھی۔ تو میری آنکھ کی پتلی تھا، اب میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔‘‘
بسا اوقات مدح گوئی حالات کے دھارے کو دوسرے رخ پر پھیر دیتی۔ بنی انف شرم کے مارے اپنے آپ کو بنی انف نہیں کہلواتے تھے بلکہ بنی قریع کہلواتے تھے۔ مگر جب حطیۂ نے ان کی مدح میں شعر کہا تو وہ فخریہ بنی انف کہلوانے لگے ؎
قوم ھم الاناف ولاذباب غیرھم
ومن یسوی انف الناقۃ الذنباء
’’وہ ناک ہیں اور دوسرے لوگ دم۔ اونٹنی کی ناک اور دم کو بھلا کون ایک درجے میں رکھے گا۔‘‘
یہ امر قابل ذکر ہے کہ عرب شاعر جب مدح گستری کرتے تو باستثنائے چند وہ ان کے دل کی آواز ہوتی۔ وہ ممدوح کو مدح کے قابل نہ پاتے تو برملا کہہ دیتے ’’افعل حتی اقول‘‘ کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ تمہاری مدح کریں۔ اس زمانے کے مشہور ممدوحین میں ایک تو رؤسائے ھرم بن سنان، عامر بن ظرف، اقرع بن حالیس، ربیعہ بن مخاشن، دوسرے مناذرۂ حیرہ اور عنساسۂ شام اور ان کے امراء تھے۔
ادھر مداحین کی صفِ اول میں امشٰی، ربیع بن زیاد، نابغہ ذبیانی، منخل لشیکری، ابوزبید الطائی، معن بن اوس، زبیر بن ابی سلمٰی، حلیئہ اور حسان بن ثابت کے نام قابل ذکر ہیں۔
’’جاء الحق وزھق الباطل‘‘
جب چھٹی صدی کی آخری دہائیوں میں غلغلۂ اسلام بلند ہوا تو اس نے زندگی کے ہر دائرے میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ کفر و ضلالت کی جگہ نور و ہدایت نے لے لی۔ رسوم کہن کی بجائے شریعتِ اسلامیہ، اور تقلیدِ آبائی کی جگہ اتباعِ رسولؐ مطمحٔ نظر بن گئے۔ قرآن نے شرک کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تو زندگی کو ایک نیا رنگ اور آہنگ ملا۔ جب ہر پہلوئے حیات میں دور رس تبدیلیاں ہوئیں تو شعر و شاعری میں بھی تبدیلی کا آنا ضروری تھا۔ اب قرآن ہی فرزندانِ توحید کے فکر و نظر کا محور بن گیا۔ قرآن نے جب شعر کو ذم کے درجے میں رکھا تو وقتی طور پر حماست، تشبیب اور ہجا وغیرہ کا جاہلی غلغلہ مکمل سکوت میں بدل گیا۔ توحید و رسالت کے پرجوش آہنگ نے ہر طرح کی خطابتِ جاہلی، فصیح البیانی اور شعری روایات کو مغلوب کر لیا بلکہ کھلا چیلنج دیا۔
فَأْتُوا بِسُوْرَۃٍ مِّنْ مِثْلِہٖ وَادْعُوْا شُھَدَاءکُمْ مِنْ دُوْنِ اللہِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْن (بقرہ ۲۳)
بعض صفِ اول کے شاعروں نے تو شاعری ہی ترک کر دی۔ چنانچہ لبید بن ربیعہ (م ۶۶۲ء) نے، جو اصحابِ معلقات میں سے تھے، قبولِ اسلام کے بعد صرف ایک ہی شعر کہا اور وہ بھی تحدیثِ نعمتِ اسلام کے جذبے سے سرشار ہو کر ؎
الحمد للہ ان لم یاتنی اجلی
حتی لبست من الاسلام سربالا
’’الحمد للہ میں نے موت سے پہلے پہلے جامۂ اسلام زیب تن کر لیا ہے۔‘‘
نزولِ قرآن سے فکر و نظر کے زاویے بدلے، ذہن بدلے، دل بدلے، سوچ کے دھارے بدلے، غرضیکہ سوسائٹی کے نفسیاتی اسالیب اور اقتصادی، تہذیبی، سیاسی اور مذہبی اطوار میں ایک عظیم تغیر آ گیا۔ خیر القرون میں لوگ عقیدۂ توحید میں ’’اشد حبا اللہ‘‘ کے مقام پر جا پہنچے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت ایک پیکرِ انسانی کی ذات میں سمٹ آئی۔ عقیدتوں کا مرجع اور داعیاتِ محبت کا سرچشمہ ایک مکمل اور اکمل انسان تھا جو ان کے سامنے تھا۔ اس لیے منطقی طور پر لازمی تھا کہ جاہلی فخر و حماست، ہجو اور تغزل کو خیرباد کہہ دیا جاتا اور اگر ثناخوانی کی جاتی تو احمدِ مختار کی، اور مدح و ستائش کے اعلٰی ترین مقام پر رکھا جاتا تو محمد مصطفٰیؐ کو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں شعرِ جاہلی کے ممدوحین کے بدلے ممدوح کائنات بلکہ ممدوحِ خالق کائنات توجہ کا مرکز بنا۔ اب تک مدحیہ شعر مدیح ’’جم و کسے‘‘ کے لیے مختص تھا، اب فخرِ بنی آدم کے تا قیامت چرچے کے لیے مخصوص ہو گیا۔
افصح العرب کی نظر میں شعر
حقیقت یہ ہے کہ عرب کی جاہلی شاعری خصوصاً ہجائی اور تشبیبی شاعری قرآنی افکار سے متصادم تھی۔ جذباتی سلسلے کے اعتبار سے اس کی کڑیاں قبائلی عصبیت سے جا ملتی تھیں۔ اسلام نے عصبیتِ جاہلی کو ختم کیا تو ایسی شاعری اور شعراء کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ اب وہیں قوتیں اسلام اور قرآن کے تحریکی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگیں۔ اسی لیے قرآن نے اسے بنظرِ استحسان نہیں دیکھا ’’الشعراء یتبعھم الغاوٗن (الشعراء ۲۲۴) شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ’’وما علمناہ الشعر‘‘ (یس ۶۹) اور ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ ’’وما ھو بقول شاعر‘‘ (الحاقہ ۴۱) اور یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں۔ جیسے سرمدی الہامات سے شعر کو بمقابلۂ قرآن مقام ذم میں رکھا گیا۔
ادھر امام الانبیاء بھی عمومی طور پر شعر کی طرف راغب نہ تھے۔ ایک تو یہ کہ شاعری مقامِ نبوت سے نہایت فروتر درجے کی چیز ہے، دوسرے یہ کہ شعر سے قبائلی عصبیت ابھرتی تھی اور رسولؐ اتفاق و اتحاد کے داعی تھے۔ فرمایا ’’لان یمتلی جوف احدکم قبیحا حتی یرید خیر من ان یمتلی شعرًا‘‘ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اور متعفن ہو جائے تو شعر سے بھر جانے سے پھر بھی بہتر ہے۔ مگر غور کیا جائے تو آیاتِ کریمہ اور احادیثِ نبویؐ میں علی الاطلاق شعر کی مذمت نہیں۔ ہجائی اور ایذا رساں شاعری کی مذمت ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی سرورِ عالمؐ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شعر میں گفتگو کی۔ آپؐ نے فرمایا ’’ان من الشعر لحکمۃ و ان من البیان لسحر‘‘ بے شک شعروں میں دانائی کی باتیں ہوتی ہیں اور بعض باتیں جادو کا سا اثر رکھتی ہیں۔ شاعری کے لیے اس حوصلہ افزا ارشاد کے ساتھ لبید بن ربیعہ کا یہ شعر سنا ؎
الا کل شئی ما خلا اللہ باطل
’’آگاہ رہو کہ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے اور نعمت بالآخر زوال پذیر ہے۔‘‘
تو فرمایا ’’اصدق کلمۃ قالھا شاعر قول لبید‘‘ (بخاری) اس سے حضورؐ کے ذوقِ شعر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مزید برآں عرب کے بعض حکیم شعراء مثلاً امیہ بن ابی الصلت (م ۶۲۴ء) ورقہ بن نوفل (م ۵۹۲ء) زید بن عمرو بن نفییل (م ۶۲۰ء) اور قس بن ساعدہ (م ۶۰۰ء) کی شاعری میں اخلاقی، مابعد الطبیعاتی حقائق، خدا، رسولؐ، ملائکہ اور یومِ آخرت کے مضامین ملتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کہ سرورِ کائناتؐ امیہ بن ابی الصلت کے وہ شعر جن میں اللہ اور آخرت کا ذکر ہوتا، بڑے شوق سے سماعت فرماتے۔
نعت کا نقطۂ آغاز
جاہلی دور میں ہجا اور مدیح کا سلسلہ جاری رہا تاآنکہ اسلام آ گیا۔ قبائلی عصبیت مٹی تو نظریاتی بنیادوں پر کفار و مومنین کے درمیان مہاجاۃ ہوئی۔ عبد اللہ بن زبعری، ابو سفیان بن الحارث اور عمرو بن العاص کفار کی طرف سے مشہور ہجوگو شاعر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واٰلہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا ’’ما یمنع الذین نصر و رسول اللہ بلاحھم ان ینصروہ بالمنتقم‘‘ جن لوگوں نے اللہ کے رسولؐ کی ہتھیاروں سے مدد کی انہیں زبان سے مدد کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ پھر تین سربرآوردہ شعراء کو جواب آں غزل کے طور پر مقرر فرمایا۔ حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اس شرف سے مشرف ہوئے۔
کفار کے مقابلے میں ان کے لسانی اور شعری معرکوں سے متاثر ہو کر فرمایا ’’ھولاء النفر اشد علی قریش من نضع النبل‘‘ یہ وہ لوگ ہیں جو قریش کے لیے تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسانؓ سے فرمایا ’’اھجھم ن اللہ لھجاؤک علیھم اشد من وقع السھام فی غلس الظلام و معک جبریل روح القدس‘‘ ان کی ہجو کر، اللہ کی قسم! تیری ہجو ان کے لیے تاریکی شب میں تیر لگنے سے بھی سخت تر ہے۔ تیرے ساتھ جبریل روح القدس ہیں۔ ان شاعرانِ سحر بیان نے ایک طرف تو دشمنانِ اسلام پر ہجو کے تیر برسائے تو دوسری طرف ممدوحِ کائنات کے حضور گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ یوں اپنی تمام تر شاعرانہ صلاحیتوں کو ثنائے خواجہ گیہاںؐ کے لیے وقف کر دیا۔
یہ تو ہے نعت کے آغاز کا تاریخی و تدریجی ارتقاء۔ دوسری طرف قرآن جس کی ابتداء توحید و رسالت کے زوردار خطبوں سے ہوتی ہے، آگے چل کر معاش و معاد، اوامر و نواہی، تبشیر و انداز، معاشرت و معاملت کی جزئیات تک کو حصر ہے۔ اصل میں سرور کائناتؐ کی حیاتِ طیبہ ہی کا لفظی عکس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اس ضمن میں جب سوال کیا گیا تو بلاتامل فرمایا ’’کان خلقہ القراٰن‘‘ (ابوداؤد باب صلوٰۃ اللیل)۔ قرآن میں نعت ختم المرسلین کے چند تابناک جواہر ریزے ملاحظہ ہوں:
احمد — ومبشرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد (صف ۶)
محمد — محمد رسول اللہ (فتح ۲۹)
یس — یس والقراٰن الحکیم (یس ۱)
طہ — طہ ما انزلنا علیک القراٰن لتشقٰی (طہ ۱)
کملی والے — یا ایھا المزمل (مزمل ۱)
چادر والے — یا ایھا المدثر (مدثر ۱)
روشن چراغ — سراجًا منیرًا (احزاب ۴۶)
شاہد مبشر — انا ارسلنٰک شاھد و مبشرًا ونذیرًا (احزاب ۴۵)
نذیر — مبشرًا و نذیرًا (احزاب ۴۵)
نور — قد جاءکم من اللہ نور (مائدہ ۱۵)
سراپا ہدایت و رحمت — وانہ لھدًی (نمل ۷۷)
رحمۃ للعالمین — وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین (انبیاء ۱۰۷)
رؤف رحیم — وبالمومنین رؤف الرحیم (توبہ ۱۲۸)
یہ تو مشتے نمونہ از خردارے ہے ورنہ سارا قرآن نعتِ ختم المرسلینؐ ہی تو ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ نعت گوئی پر مشتمل ہے بلکہ خود خدائے قدوس اور اس کے فرشتے نعت گویانِ رسولؐ اور اہلِ ایمان کو وجوبی طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے ’’ان اللہ وملئکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما‘‘۔ اللہ! اگر بندہ اس پر پکار اٹھے تو بے جا نہیں بلکہ اس کی سعادت کی انتہا ہے ؎
من ایں مقام بدنیا و آخرت مذھم
اگرچہ درینیم افتند ہر دم انجمنے
قرآن کے بعد ذخیرۂ حدیث کی طرف آئیں تو اس کام میں جانیں کھپانے والے قدسی نفس لوگوں نے کوئی ۱۴ لاکھ فرموداتِ رسولؐ جمع کر دیے ہیں۔ تا قیامت ان اقوال و ارشادات کو اَن گنت لوگ دہرا دہرا کر اپنی زندگیوں کی اصلاح و فلاح میں بھی منہمک رہیں گے اور نعتِ رسولؐ کا بھی اہتمام ہوتا رہے گا۔ یوں تو سارے کا سارا ذخیرۂ حدیث نعتِ رسولؐ ہی ہے تاہم امام محمدبن عیسٰی ترمذی (۲۰۹ ۔ ۲۷۹) نے شمائل النبویہ میں، جو ۴۰۰ احادیث کا لاجواب انتخاب ہے، ۵۶ ابواب پر تقسیم کر کے سراپائے اقدس، معمولاتِ مطہر اور فضائل و شمائل رسولؐ کا حسین ترین نعتیہ مرقع پیش کر دیا ہے۔
ہاں تو سرکارِ دو جہاں کی صبوت و ملفولیت ہی میں آپ کو عوام الناس کا بہ نگاہِ تحسین دیکھنا نعتیہ طرزِ فکر کا حامل تھا، مگر عنفوانِ شباب میں تو صداقت و امانت میں بے مثال کہلایا جانا نعتِ مصطفٰیؐ ہی کی ذیل میں آتے ہیں۔ اعلانِ نبوت سے پہلے جب حجرِ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھتے ہوئے نزاع چھڑی تو آپؐ کو دیکھ کر الجھتے ہوئے لوگوں کی زبان سے بیک آواز ’’ھذا امین رضینا بہ‘‘ کے الفاظ نکلنا کتنی پیاری نعت تھی۔ حضرت جعفر طیارؓ کا نجاشی کے دربار میں خطبہ، نعتیہ خطبہ ہی تو تھا۔ ہجرت کے موقع پر ایک اعرابیہ ام معبد کی نثری نعت شمائل رسولؐ کی نہایت دلآوایز تصویر ہے۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری پر نعت ہی سے استقبال ہوا۔ پردہ نشین خواتین نے چھتوں پر آن کر یوں زمزمہ پردازی کی ؎
طلع البدر علینا — من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا — ما دعٰی للہ داع
ایھا المبعوث فینا — جئت بالامر المطاع
’’وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چودھویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ جب تک دعا کرنے والا دعا کرے ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔‘‘
اور معصوم بچیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں ؎
’’ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، واہ محمد کیا اچھے ہمسائے ہیں۔‘‘
(سیرت النبیؐ از شبلی جلد اول)
خیر القرون کے چند اہم نعت گو شاعر
صحابہ میں یوں تو کون ایسا شخص تھا جو شاعر تھا مگر ثنائے خواجہ عالمؐ میں رطب اللسان نہ ہوا۔ تاہم ۲۲ صحابہؓ کے نعتیہ اشعار روایتوں میں مل جاتے ہیں (ارمغان نعت کا دیباچہ از عبد القدوس ہاشمی)۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زبیر، حضرت عبد اللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔
امشٰی قیس (م ۶۲۹ء) جو شراب و شباب کا شاعر تھا اس نے ایک زوردار نعت سرور عالمؐ کی مدح میں لکھی، عازم بارگاہِ رسولؐ ہوا۔ ابو سفیان بن حرب کو پتہ چلا تو اس نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ اسے اس کام سے روکیں، مبادا وہ اسلام لے آئے اور نصرتِ رسولؐ کرے۔ چنانچہ انہوں نے اسے ۱۰۰ اونٹ پیش کر کے واپس بھیج دیا۔
حسان بن ثابتؓ
حسان بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو البخاری خزرجی، ان کے دادا منذر نے اوس و خزرج کے حَکم کی حیثیت سے فریقین میں صلح کروائی، مدینہ میں پیدا ہوئے۔ عمر میں حضورؐ سے کوئی آٹھ برس بڑے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے حضری شاعر تھے۔ غسانی بادشاہوں کے مداح رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ۶۰ برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ کبرسنی کی وجہ سے جہاد بالسیف سے معذور رہے۔ جب ہجائینِ قریش کے خلاف رسول اللہؐ نے شعرائے اسلام کو تحریض کی تو حسان بن ثابتؓ نے کہا کہ میں ان کی ہجو کروں گا۔ حضورؐ نے فرمایا ’’کیف تھجوھم وانا منھم‘‘ ان کی ہجو کرے گا تو کیسے جبکہ میں ان میں سے ہوں؟ جواب تھا ’’انی اسلک منھم کما تسل الشعرۃ من العجین‘‘ میں آپ کو ان میں سے یوں کھینچ نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیتے ہیں۔ ابو سفیان بن الحارث نے ہجو کی تو جوابًا کہا ؎
’’تو نے محمدؐ کی ہجو کی، میں جواب دیتا ہوں۔ اس کی اللہ کے ہاں جزا ہے۔ تو نے اس مبارک نیک اور یکسو کی ہجو کی۔ وہ امامت خداوندی کا امین ہے اور وفا اس کی خصلت ہے۔ میرے ماں باپ اور میری عزت، عزتِ محمدؐ کے تحفظ کے لیے ڈھال ہے۔‘‘
ان کا سب سے بڑا کارنامہ وفد بنی تمیم کے ایمان لانے پر نصرتِ رسولؐ ہے۔ ستر یا اَسی افراد پر مشتمل یہ وفد حاضرِ خدمت ہوا۔ پہلے خطابت میں مقارعت ہوئی پھر شعر میں مفاخرت ہوئی۔ بنی تمیم نے اپنے مشہور شاعر زبرقان بن بدر کو پیش کیا۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کو بلا کر (جو اس وقت موجود نہ تھے) فرمایا، جواب دے۔ آپ نے نعتیہ اشعار پڑھ کر مسکت جواب دیا۔ بنی تمیم دولتِ ایمان سے مالامال ہو گئے۔ ان کے یہ شعر تو ہر عربی خواں کی زبان پر ہیں ؎
’’آپؐ سے حسین تر میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپؐ سے بہتر کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپؐ ہر عیب سے یوں پاک پیدا کیے گئے گویا آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے۔‘‘
عبد اللہ بن رواحہؓ
عبد اللہ بن رواحہؓ (متوفی ۹۴ھ) آپ خزرجی تھے۔ حضورؐ کے اتنے معتمد تھے کہ اہم ترین مشن اور سفارتیں انہی کے ذمہ ہوتیں۔ ان ۱۲ نقیبوں میں شامل تھے جو بیعتِ عقبہ ثانیہ کے بعد مقرر فرمائے گئے۔ غزوۂ موتہ (۹ھ) میں سپہ سالاری کے دوسرے جانشین تھے، اسی جنگ میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قریش کو ان کے کفر کی وجہ سے طعن کرتے تھے، جبکہ دربارِ رسالت کے دوسرے شعراء حسانؓ و کعبؓ کفار کو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے ملامت کرتے تھے۔ ان کے صرف ۵۰ شعر محفوظ رہ گئے ہیں (اردو دائرہ معارف اسلامیہ)۔
کعب بن زہیرؓ
کعب بن زہیرؓ (متوفی ۲۴ھ) اسلام لانے سے پہلے حضورؐ کی ہجو کرتے تھے اور مسلمان عورتوں کے بارے میں یاوہ گوئی کرتے۔ فتح مکہ کے بعد ان کے لیے حکم تھا کہ پکڑے جائیں تو قتل کر دیے جائیں۔ مگر خوش قسمتی دیکھئے کہ اپنے بھائی کی ترغیب پر ۹ھ میں بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئے، مشہور نعتیہ قصیدہ پڑھا جس کا مطلع ہے ؎
بانت سعاد فقلبی الیوم متبول
’’سعاد چلی گئی اور آج میرا دل بیمار ہے۔ اس کی محبت میں میرا دل اس قیدی کی طرح ہے جس کا فدیہ نہیں دیا گیا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔‘‘
جب اس شعر پر پہنچے ؎
تو اس جان رافت نے اصلاح فرمائی، سیوف الہند کی بجائے سیوف اللہ کروا دیا جس سے شعر معنوی طور پر زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ ساتھ ہی پاس بیٹھے ہوئے صحابہؓ کو کعب کے شعر سننے کی تاکید فرمائی۔ جب وہ نعت پڑھ چکے تو آپؐ نے فرطِ مسرت سے اپنی چادر مبارک کعب پر ڈال دی، اس لیے اس کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں۔
کعب بن مالکؓ
کعب بن مالک (م ۵۳ھ) خزرجی تھے۔ بیعتِ عقبہ ثانیہ میں شریک تھے۔ سرورِ عالمؐ نے حسانؓ و عبد اللہ بن رواحہؓ کے ساتھ انہیں بھی قریش کی ہجو کا جواب دینے پر مامور فرمایا تھا۔ غزوۂ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ ۵۰ دن بائیکاٹ رہا پھر معافی مل گئی۔ آخری عمر میں بصارت کھو دی۔ کلام میں جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے حقیقی جوش پایا جاتا ہے۔
خیر القرون میں نعت کی شعری روایت
سرورِ دو جہاں کے حین حیات جو نعتیہ شعر لکھے گئے ان کی کڑیاں فنی طور پر ماضی کے مدیحی ادب سے جا ملتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ’’بانت سعاد‘‘ میں آغاز ذکرِ رسولؐ سے نہیں بلکہ شاعر کی محبوبہ کے ذکر سے ہوتا ہے، پھر اونٹنی کی تعریف ہے، اور پھر آخر میں مدحِ رسولؐ پر تان ٹوٹتی ہے۔ تاہم جاہلی ادب کی شعری روایت سے ہٹ کر بھی بہت سا نعتیہ کلام موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عام امراء سے سابقہ تھا، یہاں خیر البشر سے تعلق خاطر ہے۔ وہاں کسی کے بارے میں دروغ بانی کا امکان تھا مگر یہاں ہر بات ہوش و خرد کی ترازو میں تول کر عقیدت و محبت کی چاشنی کے ساتھ کہنا پڑتی تھی۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ ایک شائبہ شرک کا خدشہ، دوسرے اہانت و گستاخی رسول کا ڈر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردانِ رسولؐ نے توحید و رسالت کی الٰہی تعلیم کے پیش نظر شعری روایت کو برقرار رکھا، یہاں اہم شعری خصائص کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
(۱) محبوب کے حسن و جمال کے چشم دید مرقعے
سرورِ عالمؐ مشتاقانِ دید کے اکثر سامنے رہتے، سرتابقدم کرشمہ دامنِ دل کھینچ کھینچ لیتا۔ ماہِ عرب جب ماہِ فلک کو شرماتا تو موازنہ کرنے والے بے اختیار ہو کر پکار اٹھتے ؎
فلک یہ تو ہی بتا دے حسن و خوبی میں
زیادہ تر ہے تیرا چاند یا ہمارا چاند
ایک چاند رات جابر بن سمرہؓ کو موازنہ کرتے دیکھا تو فرمایا جابر کیا دیکھتے ہو؟ عرض کیا اے صاحبِ لولاکؐ! آپؐ کے سامنے آسمانی چاند گہنایا ہوا لگتا ہے۔ ختم المرسلینؐ اس دنیا میں تشریف کیا لائے اہلِ نظر کی نظر نوازی کا سامان پیدا ہو گیا۔ سچ فرمایا آپ کے جاں نثار چچا حضرت عباسؓ نے ؎
نحن فی ذالک الضیاء و فی النور
’’ہم لوگ اس (ہدایتِ رسولؐ) کی روشنی میں ہیں، ہدایت و استقامت کی راہیں نکال رہے ہیں۔‘‘
(۲) ایثار کے بے مثال نمونے
تربیت یافتگانِ تربیت گہِ رسولؐ میں اس قدر ایثار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ان کی عملی زندگیاں اسوۂ رسولؐ کا بہترین نمونہ پیش کرتی تھیں۔ جب عضل و قارہ کے قبیلوں نے دس حفاظ کو شہید کر دیا تو حضرت خبیبؓ نے، جو کشتگانِ خنجر تسلیم میں سے ایک تھے، تختۂ دار پر چڑھ کر بے مثال عملِ ایثار کا مظاہرہ کر دکھایا۔ دوسرے ان کی زبان سے جو اشعار ادا ہوئے وہ ایثار للرسولؐ کا نہایت عمدہ اظہار ہے۔ آخری دعا تھی ؎
’’اے اللہ! ہم نے تیرے رسولؐ کا پیغام پہنچا دیا، اب تو ہمارے حال کی خبر اپنے رسولؐ کو کر دے۔‘‘
حضرت ابو طالب اگرچہ بروایت امام بخاریؒ دولتِ ایمان سے محروم رہے مگر جاں نثاری میں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ رسول اللہ کی نعت میں ان کے اشعار آبدار ایثار کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ کیا خوب کہا عمِ رسولؐ نے ؎
واللہ لن یصلوا الیک بجمعھم
حتٰی او سد فی التراب دفینًا
فاصدع بامرک ما الیک غضاضۃً
وابشر وقر بذاک منک عیونًا
’’خدا کی قسم وہ آپ تک اپنی جمعیت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے دفن کر کے مٹی میں ٹیک لگا کر لٹا نہ دیا جائے۔ تو اپنا کام کیے جا تجھ پر کسی قسم کی تنگی نہیں اور خوش رہ اس کام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیے جا۔‘‘
(۳) حسنِ صورت کے ساتھ حسنِ سیرت کا اظہار
صدرِ اسلام کے مشتاقانِ جمال، اجمل ترین جمیلانِ کائنات کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے اور ساتھ ہی اسوۂ رسولؐ کے ایک ایک جزئیے کو اپنانے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ یہی بے تابی جب زبان پر آتی تو لغت کے قالب میں ڈھل جاتی۔ چنانچہ اس زمانے کی نعت حسنِ ظاہری کے ساتھ شمائل و فضائل کا نہایت حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ سچ کہا ثنا خوانِ رسولؐ عبد اللہ بن رواحہؓ نے ؎
’’جس کے اخلاق شاہد ہیں وہ نوعِ بشر میں سب سے بہتر پیدا کیا گیا، اس پر میری جان قربان ہو۔‘‘
عم البریۃ ضوء الشمس القمر
’’آپؐ کی فضیلتیں سب بندوں پر اس طرح ہیں جس طرح خلقت پر سورج اور چاند کی روشنی عام ہے۔‘‘
(۴) شیفتگی و وارفتگی کے اعلٰی نمونے
نعت چونکہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ہی تبیدہ دلوں کی راحتِ جان کا سامان اور مظہر وارفتگی ہے لہٰذا اصولاً ان دلدارگانِ ختم الرسلؐ کے کلام میں شیفتگی اور والہانہ پن کے اعلٰی نمونے ملنے چاہئیں جو فیضانِ رسالت سے براہِ راست بہرہ مند ہوئے۔ اس ضمن میں ام المومنین حضرت عائشہؓ وارفتۂ جانِ مصطفٰیؐ ہو کر یوں لب کشا ہوتی ہیں ؎
متی یبد فی الدجٰی الیھم جبینہ
یلح مثل مصباح الدجٰی المتوقد
’’اندھیری شب میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ۔‘‘
نیز فرماتی ہیں ؎
’’ایک آفتاب تو دنیا کا ہے اور ایک آفتاب ہمارا بھی ہے، مگر میرا آفتاب آفتابِ آسمان سے کہیں بڑھ کر روشن ہے۔‘‘
(۵) پیامِ رسولؐ کا تذکرہ
اس دور سعادت آثار میں ہر فرزندِ اسلام دل و دماغ کے ایک نہایت خوش آئند اور کیف پرور انقلاب سے روشناس ہوا۔ اس لیے تحدیثِ نعمت کے طور پر بھی پیامِ رسولؐ کا تذکرہ زبانوں پر اکثر آتا۔ تعلیماتِ رسولؐ نعتِ رسولؐ کا جزولاینفک بن گئیں۔ حضرت حمزہؓ کے یہ اشعار کس قدر تحدیثِ نعمت کا اظہار ہیں ؎
’’وہ پیغامات جن کی ہدایات احمدؐ واضح حروف والی آیات میں لے کر آئے۔‘‘
و احمد مصطفٰی فینا مطاعًا
’’اور احمدؐ برگزیدہ ہم میں مطاع ہیں اور آپؐ کے ساتھ ناملائم لفظ بھی زبان سے نہ نکالنا۔‘‘
حضرت حسانؓ یوں نغمہ پیرا ہوتے ہیں ؎
نبی اتانا بعد یاس وفترۃ
من الرسل والاوثان فی الارض تعبد
وانذرنا نارًا وبشّــر جنۃ
وعلمنا الاسلام فاللہ نحمد
(۶) قرار خاطر آشفتہ حالاں
سرورکائناتؐ کا وجود مسعود صحابہ کرامؑ کے لیے مینارۂ نور تھا۔ وہ اس سے اکتسابِ ضیاء کرتے تو ان کے دل کو تسلی اور روح کو قرار ملتا۔ وہ اس کا تذکرہ کرتے تو ان کا وجدان جھوم اٹھتا۔ آپؐ کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ و مامون پاتے۔ آپؐ کے عم زاد ابو سفیان بن الحارث کہتے ہیں ؎
’’آپؐ کے ہدایت دینے سے ہمیں کسی گمراہی کا خوف نہیں، خود رسولؐ ہمارے رہنما ہیں۔ آپؐ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں غیب کی خبریں دیتے ہیں، نہ ان کی خبر میں خامی ہوتی ہے نہ ہیرپھیر۔‘‘
(۷) میلاد النبیؐ
اس زمانے کی نعت کا ایک موضوع میلادِ رسولؐ بھی ہے۔ یہ تذکرہ عشق و محبت کی اس بلندی سے کیا گیا ہے کہ مابعد کے ادوار میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عباسؓ کا یہ شعر ملاحظہ ہو ؎
وانت لما ولدت اشرقت الارض
’’جب آپؐ کی ولادت ہوئی تو زمین چمک اٹھی، اور آپؐ کے نور سے آفاق روشن ہو گئے۔‘‘
(۸) نعت نگار کا احساس کمتری اور عفو رسولؐ
ایسے موقعے بھی آئے کہ دشمنانِ اسلام نے بزبانِ شعر حضورؐ کی ہجو کی مگر اس رحمۃ عالم نے عفو و کرم سے کام لے کر ان کو موہ لیا۔ کعبؓ بن زہیر کا یہی معاملہ تھا۔ ۔لیکن جب ضلالتِ کفر سے نکل آئے تو نعت نگاری میں بہت سے لوگوں سے گوئے سبقت لے گئے مگر اس کا آغاز صرف اعتذار ہی سے کیا۔ اگرچہ فنی طور پر جاہلی شاعری کے قصائد کا انداز قائم رکھا تاہم رحمۃ عالمؐ نے اس انداز کو بھی پسند فرمایا اور پچھلی تمام خطاؤں پر خطِ عفو کھینچ دیا۔ حضورؐ کی اس پسندیدگی سے رنگِ تغزل کے قلم کاروں کے لیے بھی جواز نکل آیا۔ کعب یوں نغمہ طراز ہوتے ہیں ؎
فقد اتیت رسول اللہؐ معتذرًا
والعفو عند رسول اللہ مقبول
’’میں رسولؐ اللہ کی خدمت میں عذر خواہ ہو کر آیا ہوں اور حضورؐ کے نزدیک معافی دے دینا پسندیدہ ہے۔‘‘
(۹) رثائی انداز
شمعِ رسالت جب اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ضیاء بار تھی تو جاں نثار پروانے اس پر نچھاور ہونے کے لیے بے تابانہ لپکتے، مگر جب ان کی آنکھوں کے سامنے سے یہ تجلیاں اوجھل ہو گئیں تو ان کی جان پر بن گئی۔ ادھر نامِ محمدؐ زبان پر آیا ادھر آنسوؤں کی جھڑی بندھ گئی ؎
جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھر آوے
اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے
چونکہ نبوت کے ماہ شبِ چہار دہم کے اوٹ میں چلے جانے کا قیامت خیز منظر ان فداکاروں میں سے اکثر کے پیشِ نظر تھا اس لیے ان کے تاثرات میں کرب ناکی بھی تھی اور احساسِ محرومی بھی۔ دردِ دل کھٹک بھی تھی اور خلش ذہن کی کسک بھی۔ اس کا اظہار بھرپور طریقے سے ان کے کلام میں بھی موجود ہے۔ محبوب سے بچھڑ جانے کے بعد عشاق دلزدہ کی زندگی بے لطف ہو گئی ؏
مرا اے کاش کہ مادر نہ زادے
سرکارِ دو جہاںؐ کے یارِ غارؓ کا دل غم و اندوہ سے کس قدر بوجھل تھا، اس کا اندازہ ذیل کے شعروں سے لگائیے ؎
فکیف الحیاۃ لفقد الحبیب
و زین المعاشر فی المشھد
فلیت الممات لنا کلنا
و کنا جمیعاً مع المھتدٰی
’’محبوب کے بچھڑ جانے سے زندگی بے کیف ہو گئی ہے۔ زینتِ دو عالم قبر میں جا سویا۔ کاش ہم سب کو بھی موت آجاتی ،اور ہم بھی اس سراپا ہدایت سے جا ملتے۔‘‘
آنکھیں تارِ اشک پرونے لگیں، شدتِ غم سے چہرے اتر گئے، بدن نڈھال ہو گئے، فضا اپنی وسعتوں کے باوصف تنگ ہو گئی، روز روشن شبِ یلدا سے تاریک تر ہو گیا۔ سورج نے روشنی کھو دی، کائنات کی نبضیں رک گئیں، پہنائی عالم غبار آلود ہو گئی، زمین و آسمان حزن و اندوہ میں ڈوب گئے۔ ایسے میں نعت میں رثائی مضامین دفعتاً در آتے تو بے جا نہ تھا۔ وہ لوگ جو رسماً شاعر نہ تھے ان کے امڈے ہوئے جذبات بھی شعر میں ڈھل کر سامنے آ گئے۔ چند الم انگیز اور کربناک نعتیہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ عثمان غنیؓ روتے نہیں تھکتے ؎
’’اے میری آنکھ بے تکان روتی جا، سردار پر رونا تیرا حق ہے۔‘‘
علی المرتضٰیؓ یوں نڈھال نظر آتے ہیں ؎
یاتو بہ اسی علی ھالک لوٰی
’’نبیؐ کو کپڑوں میں کفن دینے کے بعد میں اس مرنے والے کے غم میں غمگین ہوں جو خاک میں جا بسا۔‘‘
آپؐ کے عم زاد ابو سفیان بن الحارث کی اس سانحہ سے یوں نیند اڑی ؎
’’میری نیند اڑ گئی ہے اور رات یوں ہو گئی ہے جیسے اب ختم نہ ہو گی۔ مصیبت کی رات دراز ہی ہوا کرتی ہے۔‘‘
جگر گوشۂ رسولؐ فاطمۃ الزہراءؓ اپنے دل کے ٹکڑوں کو یوں شعری جامہ پہناتی ہیں ؎
صبت علی الایام صرن لیالیا
’’(حضورؐ کی جدائی میں) وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ٹوٹتیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔‘‘
شمس النھار و اظلم الازمان
’’آسمان کی پہنائیاں غبار آلود ہو گئیں اور لپیٹ دیا گیا دن کا سورج اور تاریک ہو گیا سارا زمانہ۔‘‘
یا فخر من طلعت لہ النیران
’’اب چاہے مشرق و مغرب آنسو بہائے ان کی جدائی پر۔ فخر تو ان کے لیے ہے جن پر روشنیاں چمکیں۔‘‘
غرض یہ وہ چند مضامینِ نعت ہیں جو خیر القرون میں چودہ صدیوں کی دوری پر بھی ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان چودہ صدیوں کے عرصے میں اسلام مشرق و مغرب کے اکناف تک جا پہنچا۔ جہاں جہاں یہ نور پہنچا وہاں نعتِ رسولؐ بحیثیت صنفِ سخن ابھری۔ فرزندانِ توحید نے نعت نگاری، نعت خوانی اور سماعِ نعت سے قلب و نظر کو روشن کیا۔ چنانچہ موید بہ روح القدس شاعرِ اسلام حسان بن ثابتؓ سے لے کر بوصیری جیسے عشاقِ رسولؐ اور امیر الشعراء احمد شوقی جیسے ہزاروں لاکھوں جادہ پیمایان راہِ محبت نے اس ذاتِ اقدس پر عقیدت کے پھول برسائے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا مگر ؏
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
کے مصداق غالب کی زبان میں یہ کہہ کر چپ ہونا پڑے گا کہ ؎
غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گذاشتیم
کاں ذاتِ پاک مرتبہ دان محمدؐ است
ان گنت مدحت طرازانِ دربارِ نبوتؐ اس بارگاہ کی قدر افزائی تو کیا کریں گے، ہاں اپنی نجات اور سرفرازی کا سامان ضرور بہم پہنچائیں گے۔ کتنے ہی حرف ناشناس سخن دان بن کر ابھریں گے۔ سچ کہا شاعرِ رسالتؐ نے ؎
ما ان مدحت محمدًا بمقالتی
’’میں نے اگر اپنے شعر سے سرورِ عالمؐ کی تعریف کی ہے تو اس سے ان کی قدر افزائی نہیں ہوئی، ہاں میرا شعر ان کی وجہ سے ضرور بلند ہو گیا ہے۔‘‘
آج مضامینِ نعت اس قدر متنوع ہیں جیسے ایک صد پہلو ہیرا جس کا ہر پہلو ایک نیا رنگ منعکس کرتا ہے۔ ہجر و فراقِ دیارِ رسولؐ، سیرتِ اطہر کے مختلف گوشے، معراجِ رسولؐ، ہجرت، مغازی، بزم آرائی، شمائل و فضائل، غمِ دل، غمِ روزگار، پیغامِ رسولؐ کی اشد ضرورت کا احساس، اپنی بے سروسامانی، سراپائے اقدس، اعترافِ گناہ، زندگی کی بے لطفی، اجتماعی طور پر امت مرحوم کی فریادیں، شفاعتِ رسولؐ کا دل خوش کن تصور، تپشِ حشر میں حضورؐ کی سایہ گستری اور رحمۃ للعالمینی ایسے مضامین نے آج اس صنف کو گلہائے رنگارنگ کا نہایت دل آویز گلدستہ بنا دیا ہے۔ اس پر اسلوبِ بیان کی جدت فرازیاں مستزاد کر لیجئے تو فنِ نعت بطور صنفِ شعر کے جان تغزل بھی ہے، ادبِ عالیہ کا معیار بھی اور معارف و حقائق کا بہتا ہوا دریا بھی۔ مختصرًا یوں کہہ لیجئے کہ شاعری (خصوصاً عربی، اردو، فارسی) سمٹ سمٹا کر ایک قدسی بانکپن کے ساتھ آج نعت کی صورت میں جلوہ گر ہو رہی ہے۔ کیوں نہ ہو جس کا تذکرہ ہے وہ بھی تو روحِ کائنات ہے۔
وصلی اللہ علٰی حبیبہ سیدنا محمدًا واٰلہ وصحبہ و بارک وسلم۔
اختِ ہارون و بنتِ عمران حضرت مریم علیہا السلام
تاریخی حقائق کی روشنی میں
محمد یاسین عابد
کتبِ تاریخ عالم میں مریم نام کی دو عورتیں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ پہلی وہ جو حضرات موسٰیؑ اور ہارونؑ کی بہن تھیں۔ حضرت موسٰیؑ اور حضرت ہارونؑ سگے بھائی تھے اور دونوں اللہ کے سچے نبی تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام عمران تھا، بائبل میں عمرام درج ہے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کی اولاد کے مقابلہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد نے زیادہ فضیلت پائی، چنانچہ بائبل مقدس میں ہے کہ
’’عمرام کے بیٹے ہارون اور موسٰی تھے اور ہارون الگ کیا گیا تاکہ وہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ پاک ترین چیزوں کی تقدیس کیا کریں اور سدا خداوند کے آگے نجور جلائیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کا نام لے کر برکت دیں۔ رہا مردِ خدا موسٰی سو اس کے بیٹے لاوی کے قبیلے میں گنے گئے۔‘‘ (۱ تواریخ ۲۳: ۱۳ تا ۱۴)
ثابت ہوا کہ خدا نے بنی ہارونؑ کو ایک الگ و اعلٰی مقام عطا فرمایا تھا جو دیگر بنی اسرائیل کو حاصل نہ تھا۔ اسی لیے موسٰی علیہ السلام کی بہن مریم کو بعد کے لوگ ہارونؑ کی بہن مریم کے نام سے یاد کرتے اور لکھتے تھے جیسا کہ بائبل میں ہے کہ
’’تب ہارونؑ کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا۔‘‘ (خروج ۱۵: ۲۰)
بنی اسرائیل کی عورتوں میں موسٰیؑ کی بہن مریم نیکی، پرہیزگاری، تقوٰی اور خدا کی حمد و ثنا کرنے میں بہت مشہور تھیں اور مردوں میں حضرت ہارونؑ اپنی مثال آپ تھے اسی لیے بائبل مقدس نے موسٰیؑ کی بہن مریم کی بجائے ہارونؑ کی بہن مریم کہا۔
تاریخ کی دوسری مشہور اور عظیم مریمؑ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی والدہ محترم ہیں۔ یہ مریمؑ پہلی مریم سے کہیں زیادہ فضیلت والی اور زہد و تقوٰی، پاکدامنی، نیکی، پرہیزگاری اور خدا کی حمد و ثنا کرنے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادتِ الٰہی میں مصروف رہنے والی عظیم ترین شخصیت تھیں۔ آپؐ تمام عمر کنواری رہیں، نہ آپ کسی کی منکوحہ تھیں اور نہ ہی منگیتر۔ ان حضرت مریمؑ کے والدِ محترم کا نام بھی عمران ہی ہے جیسا کہ کلامِ الٰہی میں ہے کہ
’’وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَان‘‘
’’اور مریم بیٹی عمران کی‘‘ (سورہ التحریم ۱۲)
بعض عیسائی علماء کہتے ہیں کہ عمران تو اس مریم کے والد کا نام ہے جو موسٰیؑ و ہارونؑ کی بہن تھی۔ لیکن ہم عرض کریں گے کہ ایک ہی نام کے بہت سے اشخاص ہو سکتے ہیں بلکہ بائبل مقدس سے بھی ثابت ہے۔ مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہوداہ، شمعون، لاوی اور یوسفؑ تھے، جبکہ حضرت عیسٰیؑ کے شاگردوں میں بھی ان ناموں کے حضرات موجود تھے۔ معترض حضرات کو یہ تو سوچنا چاہیئے کہ اگر مریم دوسری ممکن ہے تو عمران نام کا دوسرا شخص کیوں نہیں ہو سکتا۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ مانا کہ ایک ہی نام کے کئی اشخاص ہو سکتے ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں عمرانوں کی بیٹیوں کے نام بھی مریم ہی ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا تو اکثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر یوسف علیہ السلام کے والدِ محترم کا نام گرامی یعقوبؑ تھا یعنی آپ یوسفؑ بن یعقوبؑ تھے۔ اور انجیل متی کے پہلے باب سے ایک نجار کا بھی یوسف بن یعقوب ہونا ثابت ہے۔ پس اگر ایک یوسفؑ بن یعقوبؑ کے بعد دوسرا یوسف بن یعقوب ممکن ہے تو ایک مریمؒ بنت عمران کے بعد دوسری مریمؑ بنت عمران کیسے غیر ممکن ہو سکتی ہے؟
بعض عیسائی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ تحریم کی آیت ۱۲ انجیل لوقا ۳: ۲۳ کے خلاف ہے کیونکہ انجیل کے مطابق مریمؑ کے والد کا نام عیلی ہے۔ ہم عرض کریں گے کہ لوقا ۳: ۲۳ کے مطابق عیلی یوسف نجار کا باپ ہے نہ کہ مریم کا۔ چنانچہ انجیل کی عبارت اس طرح ہے:
’’جب یسوع تعلیم دینے لگا قریباً تیس برس کا تھا ۔۔۔۔ اور یوسف کا بیٹا تھا اور وہ عیلی کا۔‘‘ (لوقا ۳ : ۲۳)
انجیل مقدس کی مذکورہ بالا آیت سے یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عیلی یوسف نجار کا والد ہے نہ کہ مقدسہ مریمؑ کا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عیلی کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے یہودی دستور کے مطابق داماد یوسف کو بیٹے کی جگہ سلسلۂ نسب میں لکھا گیا۔ حالانکہ اس بات کا کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مریمؑ کے والد کا نام عیلی تھا، اس لیے یہ بے دلیل توجیہہ ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں رکھتی۔
بفرضِ محال اگر مان بھی لیا جائے کہ مقدسہ مریم کے والد کا نام عیلی ہے تب بھی قرآن حکیم کا حضرت مریمؑ کو ’’بنت عمران‘‘ یعنی حضرت موسٰیؑ و ہارونؑ کے باپ عمران کی بیٹی کہنا بھی صحیح ہے کیونکہ بزرگوں سے انتساب قرآنِ عزیز اور بائبل مقدس دونوں ہی سے ثابت ہے جیسا کہ کلام مقدس قرآن پاک میں ہے کہ:
اَمْ کُنْتُمْ شُھَدآءَ اِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِیْہِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِیْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰھَکَ وَاِلٰہَ اٰبَآئِکَ اِبْرَاھِیْمَ وَ اِسْمَاعِیْلَ وَ اِسْحَاقَ اِلٰھًا وَّاحِدًا وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ۔ (البقرہ ۲ : ۱۳۳)
’’کیا تم حاضر تھے جس وقت پہنچی یعقوبؑ کو موت؟ جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کیا پوجو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب اور تیرے باپوں (یعنی باپ دادوں) کے رب کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، وہی ایک رب اور ہم اسی کے حکم پر ہیں۔‘‘
قرآن شریف کی مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کو حضرت یعقوب کے باپ ’’اٰبَآئِکَ‘‘ کہا گیا ہے حالانکہ حضرت یعقوبؑ کے والد تو صرف حضرت اسحاقؑ ہی ہیں جبکہ حضرت اسماعیلؑ تایا اور حضرت ابراہیمؑ دادا لگتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے قرآن مجید سے سورۃ البقرہ آیت ۲۰۰ اور البقرہ ۱۷۰ اور النساء ۲۴ اور المائدہ ۱۰۴ اور الانعام ۹۲ اور الانعام ۱۴۹ اور الاعراف ۲۸ اور الاعراف ۷۰ تلاوت فرمائیں۔
انجیل کے مطابق فرشتہ نے یوسف نجار سے کہا کہ
’’اے یوسف داؤد کے بیٹے‘‘ (متی ۱ : ۲۰)
حالانکہ یوسف داؤدؑ کا نہیں بلکہ عیلی کا بیٹا تھا (دیکھو لوقا ۳ : ۲۳)۔ ظاہر ہے کہ فرشتہ نے عیلی کے بیٹے یوسف کو عزت افزائی کے لیے حضرت داؤدؑ کا بیٹا کہا تھا۔ متی ۱:۱ میں یسوع مسیحؑ کو داؤدؑ کا بیٹا اور ابراہیمؑ کا بیٹا کہا گیا ہے حالانکہ مردوں میں سے کوئی بھی شخص آپ کا باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور آپؑ کی والدہ مریمؑ بھی داؤدؑ کی نسل سے نہیں بلکہ ہارونؑ کی اولاد سے ہیں۔ اس سلسلہ سے متعلق تفصیلی بحث انشاء اللہ آگے چل کر کی جائے گی۔ فی الحال ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت مسیحؑ حالانکہ نہ تو داؤدؑ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی آپ کا داؤدؑ کی نسل سے ہونا ثابت ہے، لیکن عزت افزائی کے طور پر آپؑ کو داؤد کا بیٹا کہا گیا، جیسا کہ انجیل لوقا میں ہے کہ
’’خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا‘‘ (لوقا ۱ : ۳۳)
اسی طرح انجیل متی میں ہے کہ
’’دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر۔‘‘ (متی ۹ : ۲۷ مزید دیکھئے متی ۲۱ : ۹ اور ۱۲ : ۱۳ اور ۱۵ : ۲۲ اور ۲۰ : ۳۰ اور ۲۲ : ۴۲)
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسٰیؑ سے فرمایا:
’’میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیمؑ کا خدا اور اضحاقؑ کا خدا اور یعقوبؑ کا خدا ہوں۔‘‘ (خروج ۳ : ۶)
غور فرمائیے کہ مندرجہ بالا حضرات میں سے ایک بھی شخص موسٰیؑ کا باپ نہیں لیکن عزت افزائی کے لیے موسٰیؑ کو ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوبؑ سے کہا گیا کہ
’’میں خداوند تیرے باپ ابراہیمؑ کا خدا اور اضحاقؑ کا خدا ہوں۔‘‘ (پیدائش ۲۸ : ۱۳)
یعنی ابراہیمؑ کو یعقوبؑ کا باپ کہا گیا حالانکہ یعقوبؑ ابراہیمؑ کے بیٹے نہیں۔ یسوع مسیحؑ نے ایک مریضہ سے متعلق فرمایا:
’’یہ جو ابراہیمؑ کی بیٹی ہے جس کو اٹھارہ برس سے شیطان نے باندھ رکھا تھا۔‘‘ (لوقا ۱۳: ۱۶)
ظاہر ہے اس عورت کا باپ ابراہیمؑ خلیل اللہ نہ تھے۔ اسی طرح لوقا ۱۶ : ۲۴ تا ۳۱ میں عالمِ ارواح کے ایک منظر میں ایک شخص کا ابراہیمؑ کو ’’اے باپ‘‘ کہہ کر پکارنا اور ابراہیم کو اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارنا مذکور ہے۔ اکثر یہودی ابراہیمؑ کو اپنا باپ کہتے تھے، چنانچہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لوگوں سے فرمایا کہ
’’اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیمؑ ہمارا باپ ہے۔‘‘ (لوقا ۳ : ۸)
بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ محض نیک ہونے کی وجہ سے بھی کسی کو ابراہیمؑ کا بیٹا کہہ دیا جاتا تھا اور بدی کی وجہ سے ابلیس کا بیٹا کہا گیا جیسا کہ مسیحؑ نے یہودیوں سے فرمایا:
’’تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے۔‘‘ (یوحنا ۸ : ۳۸)
حضرت مسیحؑ نے مزید فرمایا:
’’تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔‘‘ (یوحنا ۸ : ۴۴ مزید دیکھئے یوحنا ۸ : ۵۶ اور لوقا ۱۹ : ۹)
پولس نے غیر اسرائیلیوں کو بھی محض ایمان دار ہونے کی وجہ سے ابراہیم کی اولاد قرار دیا:
’’پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیمؑ کے فرزند ہیں۔‘‘ (گلتیوں ۳ : ۷)
پولس نے رومیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ ایمان کی وجہ سے غیر اقوام کے نامختون بھی ابراہیم کے بیٹے کہلانے کے حقدار بن جاتے ہیں (دیکھو رومیوں ۴ : ۱۱)۔
ثابت ہوا کہ جس طرح صرف ایمان لانے کی وجہ سے ایسے لوگ بھی ابراہیمؑ کے بیٹے کہلائے جو ابراہیمؑ کی نسل سے بھی نہ تھے تو لازم آیا کہ ایمان کی مطابقت کی وجہ سے بھی بعض اوقات کسی شخص کو کسی ایسے شخص کا بیٹا کہا جا سکتا ہے جو دراصل اس کا باپ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ مریمؑ کے باپ کا نام عمران نہیں تھا اور یہ کہ مریمؑ موسٰیؑ و ہارونؑ کے والد عمران کی نسل سے بھی نہیں تھیں تو تب بھی قرآن مجید کا حضرت مریمؑ کو بنتِ عمران کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ (مزید وضاحت کے لیے بائبل میں رومیوں ۴ : ۱۶ اور ۹ : ۱۰)۔ ثابت ہوا کہ کسی شخص کو محض نیکی و پرہیزگاری کی بنا پر بھی کسی نبی یا نیک بزرگ کا بیٹا کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مریمؑ واقعی عیلی کی بیٹی تھیں اور یہ کہ حضرات موسٰیؑ و ہارونؑ کے باپ عمران کی اولاد سے بھی نہ تھی تب بھی قرآن پاک کا آپ کو بنتِ عمران کہنا غلط نہیں۔
جبکہ سچ تو یہ ہے کہ حضرت مریمؑ کے والد محترم کا نام واقعی عمران ہے کیونکہ قرآنِ حکیم نے حضرت مریمؑ کی والدہ محترم کو عمران کی بیوی قرار دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مریمؑ کے والد کا نام واقعی عمران ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔
’’جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب! میں نے نذر کیا تیری جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد، سو تو مجھ سے قبول کر، تو ہے اصل سنتا جانتا۔‘‘ (آل عمران ۳۵)
قرآنِ عزیز کی مذکورہ آیت کریمہ اس امر پر دال ہے کہ حضرت مریمؑ کے والد محترم کا نام دراصل عمران ہی ہے۔ اسی لیے آپ کی والدہ کو عمران کی بیوی قرار دیا گیا ہے۔ کسی شخص کو اعزازی طور پر کسی نبی یا بزرگ کا بیٹا، بھائی یا دوست تو کہا جا سکتا ہے لیکن کسی عورت کو کسی ایسے شخص کی بیوی نہیں کہا جا سکتا جو کہ اس کا شوہر نہ ہو۔ لہٰذا ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریمؑ کے والد کا نام واقعی عمران ہے۔ رہا عیلی تو اس کے لیے ہم قاموس الکتاب مطبوعہ ۱۹۸۴ء صفحہ ۶۷۸ مقالہ عیلی عالی کی یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ
’’عیلی مریم کے خاوند یوسف کا باپ‘‘ (لوقا ۳ : ۲۳)
کلامِ الٰہی قرآن پاک میں ہے:
یَآ اُخْتَ ھَارُوْنَ مَا کَانَ اَبُوْکِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا کَانَتْ اُمُّکِ بَغِیًّا۔
’’اے ہارون کی بہن! تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔‘‘ (مریم ۲۸)
بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مریمؑ کا کوئی بھائی نہ تھا اس لیے قرآن پاک کا آپ کو اختِ ہارونؑ کہنا ان کو قبول نہیں۔ یہود کے حضرت مریمؑ کو اختِ ہارون یعنی ہارونؑ کی بہن کہہ کر پکارنے کی ایک معقول وجہ موضح القرآن میں یوں درج ہے کہ
’’بہن ہارونؑ کی یعنی ہارونؑ کی بہن، دادے کا نام بولتے ہیں قوم کو جیسی عاد و ثمود، یہ تھیں اولاد حضرت ہارون میں۔‘‘
حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا بیان واقعی حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ کسی قوم یا قبیلے بلکہ سلطنت کا نام ان کے کسی بزرگ کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلاً قومِ عاد جو کہ عاد کی اولاد ہے اور قومِ ثمود جو کہ ثمود کی اولاد ہے اور قومِ لوط جو کہ لوطؑ کی اولاد ہے اور قومِ قریش جو کہ قریش کی اولاد ہیں۔ بائبل مقدس میں بھی ۔۔ کی اولاد کو صرف ۔۔ بھی کہا گیا ہے (دیکھو روت ۱ : ۲، ۶۔ تواریخ ۱۸ : ۲۔ یسعیاہ باب ۱۵)۔ اسی طرح بنی لاوی کو صرف لاوی بھی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل قوم کو بھی اکثر اوقات صرف اسرائیل ہی کہہ دیا جاتا تھا (دیکھو تواریخ ۱۷ : ۷ اور ۱۶ : ۴ اور ۱۷ : ۲۱، ۲۲ و ۲۴۔ استثنا ۶ : ۲ تا ۵۔ استثنا ۹ : ۱ اور ۱۰ : ۱۲۔ یسعیاہ ۴۹ : ۳۔ مرقس ۱۲ : ۲۹)۔ اسی طرح بنی اقرائیم کو صرف اقرائیم کہا گیا (دیکھو قضاۃ ۱۹ : ۱۶)۔ اور بنی بنیمین کو بنیمین کہا گیا (دیکھو قضاۃ ۱۹ : ۱۴ اور ۲۰ : ۱۲)۔
یعنی بنی اسرائیل کے قبائل میں یہ رواج عام تھا کہ ہر قبیلے کو اس کے کسی بزرگ کے نام سے پکارتے تھے یعنی بنی ہاررون کو صرف ہارون بھی کہا جاتا تھا۔ اور جیسا کہ ہر شخص اپنی قوم کا بھائی اور ہر عورت اپنی قوم کی بہن ہوتی ہے اسی طرح ہر اسرائیلی اسرائیلی کا بھائی اور ہر ہارونی ہارونی کا بھائی اور ہر ہارونی عورت ہارون کی بہن ہے۔ یوں یہود کا حضرت مریمؑ کو اختِ ہارونؑ کہنا بالکل درست ثابت ہوا۔
کسی شخص کا اپنی قوم کا بھائی ہونے کے کافی شواہد بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر استثنا ۵ : ۱۲ میں ہے کہ
’’اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بِکے۔‘‘
بائبل کی مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوا کہ ہر اسرائیلی اپنی قوم کا بھائی اور عورت قوم کی بہن ہے (مزید دیکھو توریت، استثنا ۱۷ : ۱۵)
مذکورہ بالا شواہد اس امر پر دال ہیں کہ ہر شخص اپنی قوم کا بھائی اور ہر عورت اپنی قوم کی بہن ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم کا حضرت مریمؑ کو ہارون کی بہن کہنا دراصل بنی ہارون کی بہن کہنا ہے جیسا کہ خزائن العرفان میں ہے کہ
’’چونکہ یہ (یعنی مریمؑ) ان کی (یعنی ہارونؑ کی) نسل سے تھیں اس لیے ہارون کی بہن کہہ دیا جیسا کہ عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ تمیمی کو یا اخا تمیم کہتے ہیں۔‘‘
اکثر اوقات اوصاف و عادات میں مماثلت کی بنا پر بھی کسی شخص کو دوسرے کا بھائی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت لوطؑ کو جو کہ حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے ہیں (دیکھو پیدائش ۱۱: ۳۱ اور۱۴ : ۱۲)۔ بائبل مقدس میں ابراہیمؑ کا بھائی کہا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:
’’تب ابراہیمؑ نے لوطؑ سے کہا میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو کیونکہ ہم بھائی ہیں۔‘‘ (پیدائش ۱۳ : ۸ اور ۱۴ : ۱۲ تا ۱۴)
اسی طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ
’’کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔‘‘ (دیکھو متی ۲۳ : ۸)
چنانچہ تمام شاگردانِ مسیح آپس میں کہلاتے تھے (دیکھو لوقا ۲۲ : ۳۲ اور یوحنا ۲۱ : ۲۳ اور اعمال ۱ : ۱۵ اور ۹ : ۳۰ اور ۱۱ : ۱۲ اور ۱۲ : ۱۷ اور ۱۵ : ۱ اور ۱۶ : ۲ و ۴۰ اور ۲۱ : ۷ و ۱۷ اور (۱) یوحنا ۳ : ۱۴ تا ۱۶ اور (۳) یوحنا ۳ : ۵ و ۱۰ اور فلیمون ۱۰۱ و ۲۰ وغیرہ)۔
پس ثابت ہوا کہ محض عادات و اوصاف میں مماثلت کی وجہ سے بھی ایک شخص دوسرے کا بھائی کہلاتا ہے بلکہ بعض اوقات مماثلت کی بنا پر ایک جگہ کو دوسری جگہ کی بہن کہہ دیا جاتا ہے، چنانچہ یوحنا کے دوسرے خط میں ہے کہ
’’تیری برگزیدہ بہن کے فرزند تجھے سلام کہتے ہیں۔‘‘ (دیکھو ۲ یوحنا ۱ : ۱۳)
کیتھولک بائبل کے مطابق اس جگہ ایک کلیسیا کو دوسری کلیسیا کی بہن کہا گیا ہے اور کلیسیا کے مسیحیوں کو بیٹے کہا گیا ہے۔
مذکورہ بالا تمام شواہد ہمارے دعوٰی کے اثبات کے لیے کافی ہیں کہ عادات و اوصاف اور عزت و عظمت میں مماثلت کی بنا پر بھی کسی شخص کو دوسرے کا بھائی کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہارونؑ اور ان کی اولاد کو عظمت کا جو مقام حاصل تھا وہ بنی اسرائیل کے تمام قبائل میں سے کسی کو حاصل نہ تھا۔ خدا نے کہا نت کے لیے ہارونؑ کو چن لیا تھا، ادھر حضرت عیسٰی علیہ السلام کی والدہ محترم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، آپ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف تھیں، ہر شخص آپ کا احترام کرتا تھا۔ یوں آپ مثیلِ ہارون تھیں اسی لیے بنی اسرائیل آپ کو اختِ ہارونؑ کے عظیم لقب سے پکارتے تھے۔ علاوہ ازیں آپ بنی ہارون سے ہونے کی وجہ سے بھی ہارون کی بہن یعنی بنی ہارون کی بہن تھیں۔
مسیحی ماہنامہ ’’کلام حق‘‘ بابت فروری ۱۹۹۰ء کے صفحہ ۹ پر ہے کہ
’’(قرآنی عیسٰیؑ) کی ماں مریم کے باپ کا نام عمران ہے اور ماں کا نام حنہ۔ یہ مریم جس کے باپ کا نام ’’قران‘‘ عمران بتایا ہے وہ موسٰی و ہارون کی بہن تھی۔‘‘ (گنتی ۲۶ : ۵۹) فرق صرف یہ ہے کہ قرآن نے عمرام کی جگہ عمران لکھ دیا ہے یعنی م کو ن سے بدل ڈالا ہے جو از رومی قواعد اور بلحاظ لغت واجب کہلاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بڑی غلطی وجود میں یہ آئی کہ لوگوں نے موسٰیؑ کی بہن مریم کو یسوع المسیح کی ماں مریم سمجھ لیا۔‘‘
جواباً عرض ہے کہ موسٰیؑ و ہارونؑ کی بہن مریم کی والدہ کا نام یوکبد ہے جب کہ حضرت عیسٰیؑ کی والدہ محترمہ حضرت مریمؑ کی والدہ کا نام حنہ ہے، جیسا کہ خود ماہنامہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ پھر موسٰیؑ و ہارونؑ کی بہن مریم کو یسوع کی ماں سمجھ کر غلطی میں مبتلا ہونے پر حیرت ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ قرآنِ عزیز میں عمرام کے م کو ن سے بدل دیا گیا ہے، ہم جواباً عرض کریں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ حضرت مریمؑ کے والد کا نام واقعی عمران ہی ہے نہ کہ عمرام جو کہ موسٰیؑ کے والد کا نام ہے۔ اگر مسیح کی والدہ کو موسٰیؑ و ہارونؑ کی بہن ثابت کرنا ہوتا تو قرآن شریف میں بنتِ عمران کی جگہ بنت عمرام لکھا جاتا اور آپ کی والدہ کا نام بھی یوکبد لکھا جاتا۔
مسیحی ماہنامہ ’’کلام حق‘‘ بابت دسمبر ۱۹۸۸ء کے صفحہ ۱۳ سلسلہ ۹ تا ۱۰ پر اناجیل اربعہ کے یسوع المسیح کی والدہ مریم کو اختِ ہارونؑ اور بنتِ عمران تسلیم کیا ہے۔ صفحہ ۱۰ پر انجیلی تعلیم کے نظریہ نمبر ۹ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت مریمؑ ہارونؑ کی اولاد سے نہیں بلکہ یہوداہ کی نسل سے تھیں۔ لیکن ہم عرض کریں گے کہ لوقا کی انجیل میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریمؑ ہارونؑ کی اولاد سے تھیں۔ چنانچہ لوقا ۱ : ۵ میں ہے کہ
’’زکریاہ نام کا ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبع تھا۔‘‘
لوقا ۱ : ۳۶ سے مذکورہ بالا الیشبع کا حضرت مریمؑ کا قریبی رشتہ دار ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ اگر زکریاہ کاہن کی بیوی الیشبع ہارون کی اولاد سے تھی تو ضروری ہوا کہ الیشبع کی قریبی رشتہ دار مریمؑ بھی ہارون کی اولاد سے ہو۔
جو لوگ مریمؑ کو عیلی کی بیٹی اور داؤد کی نسل سے قرار دیتے ہیں ان کا اصل مقصد دراصل لوقا ۳ : ۲۳ تا ۳۱ میں بیان کردہ نسب نامہ کو (جو کہ یوسف نجار کا نسب نامہ ہے) مریمؑ سے منسوب کر کے متی اور لوقا کے بیان کردہ یوسف نجار کے دو مختلف نسب ناموں کے درمیان پائے جانے والے شدید اختلاف پر پردہ ڈالنا ہے۔ حالانکہ متی اور لوقا دونوں کا دعوٰی ہے کہ وہ یوسف نجار کا نسب نامہ لکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ انجیل کے قارئین سے یہ بات مخفی ہے کہ دونوں نے یوسف کا نسب نامہ ہی لکھا ہے، اس کا بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ فرقہ پروٹسٹنٹ کی اردو ریفرنس بائبل میں متی ۱ : ۱۲ میں مذکور ریکونیاہ کے بیٹے سیالتی ایل کے ذیل میں لوقا ۳ : ۳۷ کا ریفرنس دے کر گویا یہ اعتراف کر لیا ہے کہ لوقا ۳ : ۲۷ میں مذکور سیالتی ایل بھی یہی شخص ہے جس کا ذکر متی ۱ : ۱۲ میں ہے۔
ریفرنس بائبل میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ اسی شخص یعنی سیالتی ایل کا ذکر عذرا ۳ : ۲ میں بھی موجود ہے۔ جبکہ لوقا ۳ : ۲۷ میں مذکور سیالتی ایل کا ریفرنس دیتے ہوئے بھی عذرا ۳ : ۲ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور عذرا ۳ : ۲ میں مذکور سیالتی ایل کے ذیل میں ۱۔تواریخ ۳ : ۱۷ کا ریفرنس دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ متی ۱ : ۱۲ اور لوقا ۳ : ۲۷ اور عذرا ۳۱ : ۲ اور ۱۔تواریخ ۳ : ۱۷ میں ایک ہی شخص کا ذکر ہے۔ قارئین کو یہ جان کر حیرت ہو گی کہ ۱۔تواریخ ۳ : ۱۷ میں مذکور سیالتی ایل کے ریفرنس میں عذرا ۳ : ۲ اور ۵ : ۲ اور ۱ : ۱ و ۱۲ و ۱۴ اور ۲ : ۲ و ۲۳ اور متی ۱ : ۱۲ اور لوقا ۳ : ۲۷ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی تمام مذکورہ جگہوں پر ایک ہی شخص سیالتی ایل کا ذکر ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ لوقا والے نسب نامے اور متی والے نسب نامے میں سیالتی ایل نامی دو الگ اور مختلف آدمی ہیں بلکہ ریفرنس بائبل نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دونوں نسب ناموں میں ایک ہی شخص کا ذکر ہے۔
لوقا کا بیان کردہ نسب نامہ یوسف سے ناتن بن داؤدؑ تک، اور متی تک کا نسب نامہ یوسف سے سلیمانؑ بن داؤدؑ تک پہنچتا ہے۔ اب کون عاقل یہ تسلیم کرے گا کہ ایک ہی شخص یعنی سیالتی ایل ناتن بن داؤد کی اولاد میں بھی ہے اور وہی سیالتی ایل سلیمانؑ بن داؤدؑ کی اولاد میں بھی ہے۔ البتہ ریفرنس بائبل کے اعتراف نے یہ ثابت کر دیا کہ متی اور لوقا ایک ہی شخص یوسف نجار کا نسب نامہ بیان کر رہے ہیں۔ جس سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچی کہ عیلی یوسف کا باپ ہے نہ کہ مریم کا۔ مزید مطالعہ فرمائیں، توریت میں ہے کہ
’’اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلہ کے کسی خاندان میں بیاہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے۔ یوں کسی کی میراث ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ نہیں جانے پائے گی۔ لیکن بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراث اپنے قبضہ میں رکھیں۔‘‘ (گنتی ۳۶ : ۸ تا ۹)
چونکہ حضرت مریمؑ، ہارونؑ اور یوسفؑ، سلیمانؑ کی اولاد تھے لہٰذا بمطابق حکم توریت دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی ہوا۔
آپ نے پوچھا
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
کیا امام اعظم ابوحنیفہ ؒ کا تعلق مرجئہ سے تھا؟
سوال: مرجئہ کون تھے؟ ان کے خاص خاص عقیدے کیا تھے؟ کیا یہ فرقہ اب بھی موجود ہے؟ امام ابوحنیفہ ؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مرجئہ فرقہ میں سے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ (چراغ الدین فاروق، کوٹ رنجیت سنگھ، شیخوپورہ)
جواب: عہدِ صحابہؓ کے اختتام پر رونما ہونے والے فرقوں میں سے ایک ’’مرجئہ‘‘ بھی تھا جس کے مختلف گروہوں کا ذکر امام محمد بن عبد الکریم الشہرستانی ؒ (المتوفی ۵۴۸ھ) نے اپنی معروف تصنیف ’’الملل والنحل‘‘ میں کیا ہے، اور مرجئہ کی وجہ تسمیہ ایک یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل کو ضروری نہیں سمجھتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں دنیا میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور فیصلہ آخرت تک مؤخر اور موقوف ہے۔ اس لیے انہیں مرجئہ کہا جاتا تھا جس کا معنی ہے ’’مؤخر کرنے والا گروہ‘‘۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک شخص جب توحید و رسالت پر ایمان لے آئے تو اس کو کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا اور اس کی نجات یقینی ہے۔
دراصل اسی دور میں خوارج اور بعض دیگر گروہوں نے جب اس عقیدہ کا اظہار کیا کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، تو اس کے ردعمل میں مرجئہ دوسری انتہا پر چلے گئے کہ صرف ایمان کافی ہے، عمل کی سرے سے ضرورت نہیں ہے۔ یا ایمان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کا عمل کوئی نقصان نہیں دیتا۔
جبکہ اہلِ سنت کا مذہب اعتدال و توازن کا ہے کہ ایمان کے ساتھ نجاتِ کامل کے لیے عملِ صالح شرط ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کفر لازم نہیں آتا۔ حضرت امام ابوحنیفہ ؒ چونکہ اہلِ سنت کے امام اور ترجمان تھے اور انہوں نے کبیرہ گناہ کے مرتکب پر کفر کا فتوٰی لگانے سے انکار کر دیا، تو اس طرف کے لوگوں نے الزاماً انہیں ’’مرجئہ‘‘ قرار دے دیا، حالانکہ امام صاحبؒ کا مرجئہ کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ امام شہرستانی ؒ نے ’’الملل والنحل‘‘ میں امام اعظمؒ کی طرف مرجئہ ہونے کی نسبت کا خوب تجزیہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صرف قدریہ اور معتزلہ کا حضرت امام صاحبؒ پر الزام ہے۔
معرکہ ۱۸۵۷ء اور بہادر شاہ ظفرؒ
سوال: ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی میں بہادر شاہ ظفر ؒ کا کردار کیا تھا؟ (محمد عاصم بٹ، گکھڑ ضلع گوجرانوالہ)
جواب: ۱۸۵۷ء کے معرکہ حریت میں بادشاہ ہند بہادر شاہ ظفر مرحوم مجاہدینِ آزادی کے ساتھ پوری طرح شریکِ کار تھے۔ انہوں نے والیانِ ریاست کے نام اپنے ایک خط میں لکھا کہ
’’میری پرجوش خواہش ہے کہ ہندوستان سے فرنگیوں کو ہر ممکن طریق سے نکال دیا جائے تاکہ ملک آزاد ہو جائے۔‘‘
بہادر شاہ ظفرؒ نے اس خدشہ کی بھی تردید کر دی کہ آزادی کی جدوجہد میں ان کی دلچسپی اپنے اقتدار کی خاطر ہے، چنانچہ انہوں نے لکھا کہ
’’انگریزوں کو ملک سے نکال دینے کے بعد میرا مقصد ہندوستان پر حکومت کرنے کا نہیں۔ اگر تمام راجے دشمن کو ملک سے نکالنے کے لیے تلوار نیام سے نکال لیں تو میں شاہی اختیارات اور طاقت سے دستبردار ہونے کے لیے رضامند ہو جاؤں گا۔‘‘
مجاہدین کی افواج کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے جنرل بخت خان کا تقرر بھی بہادر شاہ ظفرؒ نے کیا اور مجاہدینِ آزادی کی پوری طرح پشت پناہی کی۔ اسی ’’جرم‘‘ میں ۱۸۵۷ء کی جنگ میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد بہادر شاہ ظفرؒ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اور مقدمہ چلانے کے بعد بہادر شاہ ظفرؒ کو مجرم قرار دے کر جلاوطن کر دیا گیا۔ چنانچہ رنگون میں نظربندی کی حالت میں ۷ نومبر ۱۸۶۲ء کو ان کا انتقال ہو گیا۔ (بحوالہ ’’انگریز کے باغی مسلمان‘‘ از جانباز مرزا)
کیا علماء دیوبند نے انگریزی سیکھنے کو حرام قرار دیا تھا؟
سوال: مشہور ہے کہ علماء دیوبند نے انگریزی زبان سیکھنے کو حرام قرار دیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ (اللہ وسایا قاسم، جہانیاں)
جواب: یہ بات غلط ہے، علماء دیوبند نے انگریزی زبان اور تعلیم کے جلو میں آنے والی یورپی تہذیب و ثقافت اور انگریزی ذہنیت و کلچر کی مخالفت ضرور کی ہے اور حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں ان کا موقف درست تھا، لیکن بحیثیت زبان کے انگریزی کی مخالفت نہیں کی۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے اس سلسلہ میں ایک استفتاء کے جواب میں مندرجہ ذیل صراحت کی ہے:
’’سوال: انگریزی پڑھنا اور پڑھانا درست ہے یا نہیں؟
جواب: انگریزی زبان سیکھنا درست ہے بشرطیکہ کوئی معصیت کا مرتکب نہ ہو اور نقصان دین میں اس سے نہ آوے۔‘‘ (فتاوٰی رشیدیہ ص ۵۶۰)
ان کے علاوہ دیگر اکابر نے بھی مختلف مواقع پر اسی موقف کا اظہار کیا حتٰی کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ نے تو مالٹا کی نظربندی سے واپسی پر خود علماء کو ترغیب دی کہ وہ انگریزی زبان سیکھیں تاکہ نئے دور کے تقاضوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’فتنۂ جمہوریت‘‘
از: حکیم محمود احمد ظفر
کتابت و طباعت معیاری: صفحات ۱۹۰
ملنے کا پتہ: ادارہ معارف اسلامیہ، مبارک پور، سیالکوٹ
جمہوریت ایک سیاسی نظام کا نام ہے جو اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے اور جس کی حشرسامانیوں نے اسلام کے نام پر قائم ہونے والے نظریاتی ملک ’’اسلامی جمہوریہ پاکستان‘‘ کو بھی جولانگاہ بنا رکھا ہے۔ پاکستان میں گذشتہ چالیس سال کے دوران جمہوریت اور مارشل لاء کی عملی کشمکش اور اسلام، سوشلزم اور جمہوریت کی فکری آویزش نے ذہنی انتشار اور سیاسی انارکی کا جو اکھاڑہ قائم کر دیا ہے اس کے ہاتھوں ہماری مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی اقدار و روایات ملیامیٹ ہو کر رہ گئی ہیں اور ہوسِ زر و اقتدار نے اس افراتفری اور نفسانفسی میں اپنے اقتدار کا خوب سکہ جما لیا ہے۔
مذہب، خدا، بائبل اور کلیسا سے ذہنی طور پر آزاد ہو جانے والی یورپی اقوام کو جمہوریت راس آئی ہے اور راس آنی بھی چاہیئے کہ ان کے عقائد اور اجتماعی نظام کے درمیان کوئی فکری تضاد باقی نہیں رہا۔ مگر اسلام، خدا، قرآن اور مسجد کے ساتھ قلبی وابستگی رکھنے والے مسلم معاشرہ کو یہ جمہوریت ہضم نہیں ہو رہی اور اس سیاسی فکر کے ساتھ پے در پے ذہنی تضادات کے باعث ہضم ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جمہوریت پرست عناصر مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہی کا دور دورہ ہو اور اس کی خاطر مذہب، عقیدہ اور اقدار و روایات سمیت کسی بھی چیز کی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جمہوریت کو اسلام ہی کی ایک نئی شکل اور عین اسلام ثابت کرنے کی مہم جاری ہے۔
مولانا حکیم محمود احمد ظفر نے زیرِ نظر کتابچہ میں اسی سعی نامشکور کا جائزہ لیا ہے اور قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ موجودہ مغربی جمہوریت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے مقابلہ میں ایک الگ نظامِ سیاست ہے جس کی فکری بنیاد مذہب سے انحراف پر رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مصنف نے اسلامی نظامِ سیاست و حکومت کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے اور اسلام اور جمہوریت کے فکری، عملی اور علمی تضادات کو اجاگر کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔
’’خلاصۂ تفسیر القرآن متعلقہ حقوقِ نسواں‘‘
از: مولانا حمید الرحمٰن عباسی
کتابت و طباعت معیاری، صفحات ۶۷۲
ناشر: انجمن خدام الدین، شیرانوالہ گیٹ، لاہور
حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری قدس اللہ سرہ العزیز کے خوشہ چینوں میں مولانا حمید الرحمٰن عباسی ایک بے نفس بزرگ ہیں جو شیرانوالہ میں ہی انتہائی سادگی اور درویشی کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مرشدی حضرت مولانا عبید اللہ انورؒ کے ساتھ ایک معاون کی حیثیت سے انہوں نے سالہا سال تک دورۂ تفسیر کے طلبہ کو حضرت امام لاہوریؒ کی طرز پر قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر سے فیضیاب کیا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔
قرآن کریم کو اس کی روایتی ترتیب سے ہٹ کر مضامین کے حوالہ سے پڑھنا اور اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر قرآن حکیم کو ایک نظام اور مجموعۂ قوانین و ضوابط کی حیثیت سے پیش کرنا مولانا عباسی کا خصوصی ذوق ہے جو انہیں حضرت امام لاہوریؒ سے ودیعت میں ملا ہے اور زیرنظر مجموعہ ان کے اسی ذوق کا شاہکار ہے۔ مولانا موصوف اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں قرآن کریم کی ہدایات کو الگ الگ مجموعہ جات کی صورت میں پیش کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور اس کا آغاز انہوں نے خواتین کے حقوق و فرائض اور ان سے متعلقہ مسائل پر مشتمل زیرنظر مجموعہ سے کیا ہے جسے خلاصۂ تفسیر القرآن کی جلد خامس کا عنوان دیا گیا ہے۔
اسلام میں خواتین کے مقام و حیثیت اور ان کے حقوق و فرائض کی وضاحت کے ساتھ ساتھ نکاح، طلاق، عدت، وراثت، حدود، شہادت، پردہ اور دیگر ضروری امور کے بارے میں قرآن و سنت کی ہدایات و احکام کو اچھے پیرائے میں بیان کر کے مصنف نے مغربی تہذیب کی حمایتی لابیوں کی یلغار کے اس دور میں وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف نظام ہائے زندگی کی کشمکش کی اس فضا میں قرآن کریم کے بحیثیت نظامِ زندگی مطالعہ کے ذوق کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے اور مولانا عباسی کی یہ کاوش اس سمت ایک بہتر پیشرفت ہے۔
’’وہ عہد کا رسولؐ‘‘
مرتب: مولانا عبد اللطیف مسعود
صفحات ۱۳۰ قیمت ۱۵ روپے۔ کتابت و طباعت گوارا
ملنے کا پتہ: مدینہ پلاسٹک مرکز، مین بازار ڈسکہ، ضلع سیالکوٹ
مصنف نے اس کتابچہ میں جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے بارے میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بائبل سے بھی دلائل پیش کیے ہیں، اور سابقہ آسمانی کتب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشگوئیوں اور بشارات کے علاوہ سید المرسلینؐ کی صداقت و رسالت پر غیر مسلم مشاہیر کے اقوال بھی اچھے انداز میں جمع کر دیے ہیں اور اس سلسلہ میں مسیحی مصنفین کے اعتراضات کا بھی مسکت جواب دیا ہے۔
’’تجلیاتِ حبیبؒ‘‘
مصنف: مولانا محمد نعیم اللہ فاروقی
صفحات ۶۸ کتابت و طباعت عمدہ
ملنے کا پتہ: جامع مسجد زینب، بند روڈ، لاہور ۲۵
حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز ہمارے دور کے اہل اللہ میں سے تھے جنہوں نے اپنے اسلاف کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں میں اللہ اللہ کا ذوق بیدار کرنے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کی۔ ان کے خلیفہ مجاز مولانا محمد نعیم اللہ فاروقی نے اس رسالہ میں اپنے شیخ کے حالاتِ زندگی، جہد و عمل اور ملفوظات کو پیش کیا ہے جس کا مطالعہ نوجوان علماء کے لیے بالخصوص افادیت کا باعث ہو گا۔
’’سازش کا پردہ چاک ہوتا ہے‘‘
مصنف: محمد اسلم رانا
صفحات ۴۲ قیمت ۴ روپے
ملنے کا پتہ: (۱) اسلامی مشن، سنت نگر، لاہور (۲) مرکز تحقیق مسیحیت، ملک پارک، شاہدرہ، لاہور
جناب محمد اسلم رانا ایک عرصہ سے پاکستان میں عیسائی اداروں کی تبلیغی سرگرمیوں کے تعاقب کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں اور حالات کی نامساعدت کے باوجود علماء اسلام کو ان کی دینی ذمہ داری کے اس اہم پہلو کی طرف توجہ دلانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ زیرنظر مضمون میں انہوں نے سندھ کے ناگفتہ بہ حالات کے پس منظر میں مسیحی اداروں اور ہندوؤں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کو بے نقاب کیا ہے اور مختلف حوالوں سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف غیر مسلم اقلیتوں کی سازشوں سے پردہ اٹھایا ہے۔
امراضِ گردہ و مثانہ
پتھری کے اسباب
حکیم محمد عمران مغل
ہمارا جسم پانی سے لبریز ہے جس میں کیمیائے حیات کے سبب آلودگی ہوتی رہتی ہے۔ غذا کی تلچھٹ اور خون میں تقریباً چودہ سے زائد نمکیات یا اجزا ہر وقت شامل رہتے ہیں۔ اس تلچھٹ اور نمکیات کی زیادتی کو خون سے جدا کر کے براستہ پیشاب خارج کرنا گردوں کا کام ہے، اس لیے انہیں جسم کی چھلنی بھی کہا جاتا ہے۔ گردے دو چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں جو کمر سے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب قدرت نے آویزاں کیے ہیں۔ حجم اور قامت میں انڈے سے بڑے تقریباً ساڑھے چار انچ لوبیا کی مانند۔ قدرت کی کاریگری ملاحظہ فرمائیں کہ ان میں بیس لاکھ نلکیاں ہیں جنہیں ایک سیدھ میں کیا جائے تو اَسّی میل کا فاصلہ بنتا ہے ’’فتبارک اللہ احسن الخالقین‘‘۔
مشروبات میں جس قسم کی غلاظت ہو گی یا پانی میں جتنے زائد نمکیات جو ہمارے جسم کو ضرورت نہ ہوں، وہ گردے الگ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ خون سے زہریلی ادویات، جراثیمی زہر، جانوروں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے زہر، اور فالتو نمکیات کو کسی صورت جسم میں نہیں چھوڑتے۔ یہ پاسبانوں کی طرح سدا چوکس اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔
جوان صحت مند آدمی چوبیس گھنٹہ میں ایک سے ڈیڑھ لیٹر تک پیشاب کرتا ہے جس میں پانی اور خون کی غلاظت اور نمکیات ہوتے ہیں۔ اگر گردے اور مثانہ صحت مند ہوں تو پندرہ اونس پیشاب انسان روک سکتا ہے، مگر کمزوری کی صورت میں بمشکل پانچ اونس ہی رکے گا، اور بڑھاپے میں مثانہ تقریباً کمزور ہو جاتا ہے اس لیے بار بار پیشاب آتا ہے۔ جوانی میں اگر پیشاب بار بار آئے تو مثانہ میں نقص واقع ہو گا جیسے مثانہ کی خراش یا دیگر امراضِ مثانہ۔ اگر پیشاب کو کافی دیر روکے رکھیں تو ورمِ مثانہ کے علاوہ پتھری بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سواری کی حالت میں سواری روک کر بہرصورت پیشاب کر لیں۔
بظاہر کوئی تکلیف نہیں مگر بار بار پیشاب آئے یا بلا ارادہ پیشاب نکل جائے تو پھر ہاضمہ لازمی خراب ہو گا یا حرام مغز پر چوٹ لگنا، ٹھنڈی اور تیز اشیاء کا استعمال، نیچے کے دھڑ کا فالج۔ اسی طرح اگر تین سال سے زائد عمر کا بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو اس کے ہاضمہ کی طرف توجہ دیں۔ اس کے پیٹ میں کیڑے بھی یقیناً ہوں گے، اس کے حوض گردہ کی یا مثانہ میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ جسم کے دوسرے اعضاء کی نسبت اپنے جثہ اور قد و قامت کے لحاظ سے انہیں جتنا کام کرنا چاہیئے یہ اس سے دس گنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تو اتنا کام کریں مگر ایک ہم ہیں کہ سارا سارا دن بیٹھے جانوروں اور چوپاؤں کی طرح الابلا کھائے جاتے ہیں اور جسم کو حرکت دینے میں عار سمجھتے ہیں، جس کا سبب پتھری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔
یاد رکھیں کہ گردوں میں پتھری اور ریت کا مرض کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، تاہم جوانی اور بڑھاپے میں یہ زیادہ زور آزمائی کرتا ہے۔ پتھری کے مریض تقریباً سو فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں جو سست اور سہل الوجود کاہل بیٹھے بیٹھے منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ مرغن میٹھی اور لحمی غذائیں کھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ
وہ بھولے ہوئے ہیں عادت خدا کی
کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی
چنانچہ انہی لوگوں کی اولاد میں بھی یہ مرض سرایت کر جاتا ہے اور موروثی سلسلہ چل نکلتا ہے۔
علامات
گردوں میں عموماً دو قسم کی پتھریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں پہلی قسم کو یورک ایسڈ، دوسری کو اوگزے لیٹ آف لائم۔ یورک ایسڈ سے مراد ہے جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، ورزش یا کام کاج قطعی نہیں کرتے، جس سے پانی کی طلب ان کو تقریباً نہیں رہتی، یہ پتھری بھوری سرخی مائل سطح ہموار لیے ہو گی، تو سمجھ لیں کہ اس مریض نے گوشت اور لحمی اجزاء سے بھرپور خوراک کھائی مگر اکثر زندگی سستی میں گزاری۔ فاسفیٹ یا اوگزے لیٹ سے بننے والی پتھری ان مریضوں میں ہو گی جن کا ہاضمہ خراب اور جگر کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ گوشت کی بجائے چکنائی اور میٹھی اشیاء کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔
آپ کو زندگی میں یہ مشاہدہ بھی ہوا ہو گا کہ یہ تمام بدپرہیزی بھی ہو رہی ہے مگر صحت پھر بھی ٹھیک اور گردہ و مثانہ کی کوئی بیماری بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں کولہو کے بیل کی طرح جتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آجائے تو گھبراتے نہیں اور ان کا کھایا پیا سب پسینے کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔
گردے میں پتھری کی علامت یہ ہو گی کہ پسلیوں کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب ہلکا ہلکا درد ہو گا۔ دوڑنے یا ہچکولوں سے درد میں اضافہ ہو گا۔ یہ درد کبھی کنج ران اور کبھی خصیوں میں بھی ہو گا۔ پتھری جب حرکت کرے گی تو درد سے مریض تڑپ اٹھے گا اور پیشاب کے ساتھ خون کے ذرات بھی آئیں گے۔
یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ خون مثانہ کی پتھری سے بھی آئے گا، اس لیے اس فرق کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر خون پیشاب میں شامل ہو کر آئے تو یہ گردوں یا حالبین کی نالیوں سے ہو کر آئے گا۔ اگر پیشاب کر چکنے کے بعد خون آئے تو مثانہ کی وجہ سے۔ اگر خون پیشاب کرنے سے پہلے آئے تو محیرائے بول یعنی اس نالی سے جو مثانہ سے پیشاب لاتی ہے۔ اگر پیشاب میں پیپ آئے تو پتھری کی رگڑ سے گردوں میں ورم پیدا ہو چکا ہے۔ مریض کو پتھری کی خراش سے قے آتی ہے۔ اگر مریض کو پیشاب کی نالی میں پیڑو کے نچلے حصہ میں یا پیشاب کی نالی کے آخری سرے میں درد ہو تو اب پتھری مثانہ میں ہو گی جو کہ پیشاب کر چکنے کے بعد ٹیس بھی ہو گی۔ پیشاب بار بار آئے گا اور فراغت کے بعد بھی حاجت بدستور رہے گی۔ اگر پتھری مثانہ کے منہ پر آجائے، پیشاب رک جائے گا۔
علاج و پرہیز
اگر پتھری بہت بڑی ہے تو پھر مجبورًا آپریشن ہی کروانا پڑے گا، حالانکہ آپریشن کے بعد بھی پتھری لازمی پیدا ہو گی کہ یہ اس کا فطری علاج نہیں ہے۔ اس لیے روس کی حکومت نے اس سال مارچ میں بھارت سے معاہدہ کر کے ایک مکمل آیورویدک ادارہ کی بنیاد ڈالی جہاں وہی ہزاروں سال پرانا طریقہ پھر سے رائج ہو گا۔ انجکشن کے بارے میں ۱۹۸۴ء میں کیلیفورنیا کے بائیوٹیکنالوجی کے ماہرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو دوا منہ کے ذریعے کھلائی جائے وہی اصل اور فطری علاج ہے۔
قصہ مختصر یہ کہ آپ صبح شام خوب سیر کریں کہ خوب پسینہ خارج ہو اور کام کاج میں اپنے جسم کو تھکا دیں تاکہ کھایا پیا اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ سخت محنت اور ریاضت آپ کو کندن بنا دے گی۔ یہ دوا پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے انشاء اللہ خارج کر دے گی۔ حجر ایہود اور سنگ سرماہی کو باریک سرمہ کی طرح پیس کر صبح اور رات کو ایک ایک ماشہ گرم پانی سے کھائیں۔ پھر صبح شام جوارش زرعونی سادہ چھ چھ ماشہ شربت بزوری ۴ تولے کے ہمراہ کھائیں۔ سوتے وقت کلتھی کی دال کا شوربہ بھی لازمی پیئں۔ کبھی کبھی جوارش جالینوس بھی چھ چھ ماشہ کھانے کے بعد مدت العمر کھاتے رہیں۔
غذا میں چھوٹے گوشت کا اور کالے چنوں کا شوربہ، چپاتی، مونگ ارہر کی دال، روغن بادام، پستہ، انجیر، تربوز، انگور، انناس اور ترش میوے کے بغیر بالکل پرہیز رکھیں۔ پانی جتنا پیا جا سکے پیئں۔ میدہ کی تمام اشیاء سے قطعی پرہیز، ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ بھی مکمل طور سے پینا بند کر دیں۔
معاشرتی زندگی کے آداب
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
انسان کا مدنی الطبع ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتِ ازلیہ کا کرشمہ ہے۔ اجتماعی زندگی کے بغیر اور ابنائے نوع کے تعاون سے بے نیاز ہو کر وہ اپنی زندگی کی تدبیر، تعمیر اور تحسین نہیں کر سکتا۔
معاشرتی زندگی ایسے آداب کے بغیر بسر ہو نہیں سکتی جو افراد کے آپس میں محبت، تعاون اور تناصر کا رشتہ پیدا کریں اور پھر اس رشتہ کو برقرار اور استوار بھی رکھیں۔ اگر ان پر برے عوامل اثر انداز ہو کر ان میں فساد پیدا کریں تو ان عوامل کا استیصال کرنا چاہیئے اور ایک بار پھر نفرت و دشمنی کی بجائے باہمی الفت و محبت کی طرف لوٹنے کی تدبیر کرنا چاہیئے۔ اس لیے کہ باہم میل جول کے مفید نتائج تب ہی ہاتھ آتے ہیں جب آپس میں محبت اور الفت کا رشتہ قائم ہو۔
معاشرتی زندگی میں انسان کا جن لوگوں سے زیادہ قریبی تعلق رہتا ہے وہ اس کے ذوی الارحام (قریبی رشتہ دار)، پڑوسی اور دیگر دوست، آشنا اور متعلقین ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم درس، ہم پیشہ اور ایک ہی حلقۂ خدمت و ارادت کے ہم نشین وغیرہ وغیرہ۔ ان کو چاہیئے کہ
- آپس میں ملاقات کا سلسلہ جاری رکھیں،
- مناسب موقعوں پر ایک دوسرے کو ہدیہ اور پیشکش دیا کریں،
- ایک دوسرے سے دوری کے وقت خط و کتابت کے ذریعے حال و احوال معلوم کیا کریں،
- امورِ معاش میں ایک دوسرے کی حتی المقدور اعانت و امداد کریں،
- مصیبت کے وقت ہمدردی سے دریغ نہ کریں،
- گفتگو میں خوش طبعی اور شیریں زبانی کو ملحوظ رکھیں،
- اور تکالیف و شدائد میں ایک دوسرے کی غم گساری کریں۔
انہی باتوں سے الت بڑھتی اور محبت زیادہ ہوتی ہے اور انہی پر عمران و تمدن کی بقاء کا دارومدار ہے۔
(البدور البازغۃ مترجم ص ۱۴۶)
حکمران جماعت اور قرآنی پروگرام
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
قانون کی پابندی کا انتظام ایک جماعت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور وہ حکومت کرنے والی جماعت ہی ہو سکتی ہے۔ قانون کا انتظام کرنے والی جماعت کا فرض ہے کہ وہ امانت دار ہو اور اپنا فرض ادا کرنے والی ہو۔ صحیح طور پر قانون کی پابندی کرنے والی جماعت کا سب سے پہلا کام یہ ہو گا کہ وہ قانون کی تعلیم عام لوگوں کو اسی طرح دینا شروع کرے جیسے باپ اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے۔
پھر قانون کی مخالفت کرنے والوں کو سزا دینا بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہو گا۔ وہ مخالف جماعتیں یا تو اس پارٹی کے اندر شامل ہوں گی یا باہر۔ جو اندر ہوں گی انہیں قانون توڑنے کی سزا دینے کا نام تعزیر ہے اور جو باہر ہوں گی ان سے جنگ لڑنی پڑے گی۔ تعزیر اور جنگ دونوں میں جتنی قوت استعمال کرنے کی ضرورت ہے اتنی ہی استعمال کرنی چاہیئے۔
یہ قانون چلانے والی پارٹی عام لوگوں سے فقط قانون کی پابندی کرائے گی، اور ان کی طرح خود بھی اس قانون کی پابندی کرے گی۔ وہ ان سے اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کرائے گی کیونکہ یہ ظلم ہے۔ قانون کی صحیح پابندی کے لیے زبان میں اصطلاحی لفظ تکلیف بولا جاتا ہے۔ (ترجمہ حجۃ البالغۃ تمہید باب ۶)
جو امت قرآن کریم کا پروگرام نہیں اپنائے گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو گی۔ مسلمان قرآن کی عالمی تنظیمی دعوت کا پروگرام لے کر اٹھے تھے اور پھر اپنی اس تنظیمی دعوت میں کامیاب ہو گئے، اور صرف پچاس سال کی مدت یعنی واقعہ صفین کی تحکیم تک ہوا۔ اب جو کوئی امت تنظیمی دعوت لے کر اٹھے گی تو وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو گی جب تک وہ قرآن کے پروگرام کو نہ اپنائے گی۔ (الہام الرحمٰن)
ستمبر ۱۹۹۰ء
خلیج کا آتش فشاں
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
کویت پر عراق کے جارحانہ قبضہ اور سعودی عرب و متحدہ عرب امارات میں امریکی افواج کی آمد سے یہ خطہ ایک ایسے آتش فشاں کا روپ اختیار کر چکا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور خلیج میں پیدا ہو جانے والی خوفناک کشیدگی کے حوالہ سے دنیا پر تیسری عالمگیر جنگ کے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔
کویت دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اور اس کی کرنسی عراق کے قبضہ سے پہلے تک دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی کرنسی رہی ہے لیکن صرف دو گھنٹے کے عرصے میں اس کے عراق کے قبضے میں آجانے سے یہ بات ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے کہ مسلم ممالک جب تک اپنے وسائل کو دفاع و حرب کے لیے وقف نہیں کریں گے ان کی دولت ان کے کسی کام کی نہیں ہے، اے کاش کہ یہ نکتہ اب بھی عرب حکمرانوں کے ذہن میں آجائے۔
کویت پر عراق کا یہ جارحانہ حملہ بلاشبہ ایک آزاد اور خودمختار ملک کی آزادی کو سلب کرنے کا عمل ہے جو اقوام عالم کے مسلّمہ اصولوں کے منافی ہے اور اس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن عجلت اور گھبراہٹ میں امریکی فوجوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں براجمان ہو جانے کا موقع فراہم کرنا بھی سنگینی میں اس سے کم نہیں ہے اور اس سلسلہ میں عالم اسلام میں پایا جانے والا اضطراب اور بے چینی بلاوجہ نہیں ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اسلامی سربراہ کانفرنس کا ہنگامی اجلاس طلب کر کے مشترکہ دباؤ کے ذریعے عراق کو کویت سے اور امریکہ کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے فوجیں واپس بلانے پر مجبور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم خلیج کے آتش فشاں کو پھٹنے اور دنیا بھر میں تباہی پھیلانے سے روک سکتے ہیں۔
علومِ حدیث کی تدوین — علماء امت کا عظیم کارنامہ
شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر
آنحضرت صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور پیارے طریقوں کی حفاظت جس طرح اس امتِ مرحومہ نے کی ہے دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جھوٹی اور غلط بات آپ کی طرف منسوب کرنے کی سختی سے تردید فرمائی ہے وہ اہلِ اسلام کے ہاں اظہر من الشمس ہے اور حدیث ’’من کذب علیّ متعمدا فالیتبوا مقعدہ من النار‘‘ متواتر احادیث میں درجہ اول پر ہے۔
آپ کے الفاظ کی نگرانی مہماتِ شریعت اور اساسی و بنیادی امور کے متعلق تو الگ رہی حتٰی کہ الفاظ کی بھی نگرانی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس صحیح حدیث سے ہی بہت کچھ اخذ کیا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براءؓ بن عازبؓ کو سونے کے وقت کی دعا بتلائی جس میں یہ الفاظ بھی تھے ’’ونبیک الذی ارسلت‘‘ (یعنی میں تیرے نبی پر بھی ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے)۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعائیہ کلمات آپؐ کو سنائے تاکہ ان میں غلطی نہ رہ جائے مگر میں نے یہ الفاظ پڑھ دیے ’’وبرسولک الذی ارسلت‘‘ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا ’’لا، ونبیک الذی ارسلت‘‘ (بخاری ج ۱ ص ۳۸ و ج ۲ ص ۹۳۴)۔ یعنی وہی الفاظ پڑھو جو تمہیں بتلائے گئے ہیں۔ غور فرمائیں کہ جب دعا میں آپؐ نے الفاظ کی پابندی کا یہ سبق دیا ہے تو احکامِ دین اور بنیادی امور کے بارے الفاظ کی پابندی کا خیال کیسے نظرانداز کیا جا سکتا تھا؟
حضراتِ محدثین کرامؒ اور فقہائے عظام نے حدیث کی سند اور معنی کی حفاظت کے لیے تقریباً پینسٹھ علوم ایجاد کیے ہیں جن کی روشنی میں احادیث کی صحت و سقم اور معانی کی درستی اور نادرستی سے بخوبی آگاہی ہو سکتی ہے۔ ہم طلبۂ علم کی معلومات کی خاطر اصولِ حدیث کی چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس امتِ مرحومہ نے کس محنت شاقہ سے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیاری باتوں کی حفاظت کی ہے۔
سب سے پہلے فنِ اصطلاحِ حدیث میں قاضی ابو محمد حسنؒ بن عبد الرحمٰنؒ بن خلاد الرامہرمزی (المتوفی۲۶۰ھ) نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ’’المحدث الفاصل بین الراوی والراعی‘‘ ہے۔ اس کے بعد متعدد علماء امت نے نظم و نثر میں اس فن پر طبع آزمائی فرمائی اور عمدہ و نفیس کتابیں لکھ کر عالمِ اسباب میں امتِ پر احسان کیا اور امت کو فائدہ پہنچانے میں ایک دوسرے پر مسابقت کی ہے۔ بعض مشہور کتابوں کے نام مع سنینِ وفاتِ مصنفین درج ذیل ہیں۔
کتب اصولِ حدیث اور شروحِ حدیث
اکثر کتب اصولِ حدیث اور شروحِ حدیث میں ان میں سے بعض مصنفین یا ان کی کتابوں کے نام آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کتاب کا نام ہوتا ہے تو مصنف کا نام ساتھ نہیں ہوتا، اور اگر مصنف کا نام ہوتا ہے تو کتاب کا نام نہیں ہوتا، اور اگر دونوں کا نام ہو تو سنِ وفات کا ذکر ساتھ نہیں ہوتا اور طلبۂ علم کی تشنگی دور نہیں ہوتی۔ اس لیے بتوفیق اللہ تعالٰی و تائید ہم نے حتی الوسع ان سب باتوں کو ملحوظ رکھا ہے لیکن سنینِ وفات کی ترتیب ایک خاص مجبوری کی وجہ سے نظرانداز کر دی گئی ہے لیکن اس میں بھی اہلِ علم کے لیے انشاء اللہ العزیز خاص فائدہ ہو گا۔
| نام کتاب |
نام مصنف |
تاریخ وفات |
معرفت علوم الحدیث
|
امام ابو عبد اللہ محمدؒ بن عبد اللہ الحاکم
|
۴۰۵
|
| مدخل |
امام ابو عبد اللہ محمدؒ بن عبد اللہ الحاکم |
۴۰۵
|
المستخرج علٰی علوم الحدیث
|
حافظ ابو نعیم احمدؒ بن عبد اللہ الاصفہانیؒ
|
۴۳۰
|
| الکفایۃ |
حافظ ابوبکر احمدؒ بن علی الخطیب البغدادیؒ
|
۴۶۳
|
الجامع لآداب الشیخ والسامع
|
حافظ ابوبکر احمدؒ بن علی الخطیب البغدادیؒ |
۴۶۳ |
مالا یسع المحدث جہلہٗ
|
ابوحفص عمرؒ بن عبد المجید قرشیؒ
|
۵۸۰
|
الخلاصہ فی معرفۃ الحدیث
|
ابو محمد الحسینؒ بن عبد اللہ الطیبیؒ
|
۷۴۳
|
مقدمہ فی علم الحدیث
|
ابو الخیر محمدؒ بن محمد الجزریؒ
|
۸۳۳
|
تذکرۃ العلماء فی اصول الحدیث
|
ابو الخیر محمدؒ بن محمد الجزریؒ |
۸۳۳
|
تنقیح الانظار فی علوم الآثار
|
سید محمد ابراہیم المعروف بابن الوزیرؒ
|
۸۶۰
|
بلغۃ الحثیث فی علوم الحدیث
|
یوسفؒ بن الحسنؒ بن عبد الہادی الدمشقیؒ
|
۹۰۹
|
المختصر فی مصطلح اہل الاثر
|
عبد اللہ الشنشوری الشافعی الفرضیؒ
|
۹۰۹
|
خلاصۃ الفکر فی شرح المختصر
|
عبد اللہ الشنشوری الشافعی الفرضیؒ |
۹۰۹
|
اشرافات الاصول فی احادیث الرسول
|
محمدؒ بن اسحاق القونویؒ
|
۶۷۲
|
المختصر الجامع لمعرفۃ علوم الحدیث
|
سید شریف علیؒ بن احمد الجرجانیؒ
|
۸۱۶
|
ظفر الامانی فی مختصر الجرجانی
|
مولانا عبد الحی لکھنویؒ
|
۱۳۰۴
|
قصیدۃ الغرامیۃ
|
ابو العباس شہاب الدین احمد اللخمی الاشبیلیؒ
|
۶۹۹
|
شرح الغرامیۃ
|
ابوا العباس احمدؒ بن الحسین لقسمطینیؒ
|
۸۱۰
|
شرح الغرامیۃ
|
محمدؒ بن ابراہیم الخلیل التتائی المالکیؒ
|
۹۲۷
|
شرح الغرامیۃ
|
شمس الدین ابو الفضل محمدؒ بن محمدؒ الدسجی العثمانی الشافعیؒ
|
۹۴۷
|
شرح الغرامیۃ
|
یحیٰیؒ بن عبد الرحمٰن الاصفہانی الشہیر بالقرانی الشافعیؒ
|
۹۶۰
|
شرح الغرامیۃ
|
محمدؒ بن الامیر الکبیرؒ
|
۱۱۸۰
|
شرح الغرامیۃ
|
الحافظ القاسمؒ بن قطلوبغا الحنفیؒ
|
۸۷۸
|
حاشیہ نزہۃ النظر
|
الحافظ القاسمؒ بن قطلوبغا الحنفیؒ |
۸۷۸
|
| بیقونیۃ |
عمرؒ بن محمدؒ بن فتوح البیقونی الدمشقی الشافعیؒ
|
۱۰۸۰
|
شرح البیقونیۃ
|
شیخ محمدؒ بن صعدان الشہیر بجاد المولٰی الحاجری الشافعیؒ
|
۱۲۲۹
|
| شرح البیقونیۃ |
عطیۃ الاجہوری الشافعیؒ
|
۱۱۹۰
|
| شرح البیقونیۃ |
محمدؒ بن عبد الباقیؒ بن یوسف الزرقانیؒ
|
۱۱۲۲
|
العرجون فی شرح البیقون
|
نواب محمد صدیقؒ بن حسن خان القنوجیؒ
|
۱۳۰۷
|
البہجۃ الوضیۃ
|
علامہ الشیخ محمود نشابہؒ
|
۱۳۳۸
|
الاقتراح فی بیان الاصطلاح
|
محمدؒ بن علیؒ ابن دقیق العیدؒ
|
۷۰۶
|
الخلاصہ فی اصول الاثر
|
شرف الدین حسنؒ بن محمد الطیبیؒ
|
۸۱۶
|
التقاسیم والانواع
|
محمدؒ بن حبانؒ بن احمد الستبیؒ
|
۳۵۴
|
الثواب فی الحدیث
|
عبد اللہؒ بن محمدؒ بن جعفرؒ بن حیان الاصفہانیؒ
|
۔۔۔
|
الاعلام فی استیعاب الروایۃ عن الائمۃ الاعلام
|
علیؒ بن ابراہیم الغرناطیؒ
|
۵۷۷
|
المغنی فی علم الحدیث
|
عمرؒ بن بدرؒ بن سعید الموصلی الحنفیؒ
|
۶۲۲
|
جامع الاصول فی الحدیث
|
محمدؒ بن اسحاق القونویؒ
|
۶۷۲
|
المغیث فی علم الحدیث
|
احمدؒ بن محمدؒ بن الصاحبؒ
|
۷۸۸
|
المقنع فی علوم الحدیث
|
حافظ ابن الملقنؒ
|
۸۰۴
|
المنظومۃ فی اصول الحدیث
|
احمدؒ بن محمد الشمنی ؒ
|
۸۷۲
|
منیع الدر فی علم الاثر
|
محمدؒ بن سلیمان الکافیجیؒ
|
۹۷۸
|
الروض المکلل والورد المحلل
|
امام جلال الدین سیوطیؒ
|
۹۱۱
|
تدریب الراوی
|
امام جلال الدین سیوطیؒ |
۹۱۱
|
قطر الدر
|
امام جلال الدین سیوطیؒ |
۹۱۱
|
مقدمہ ابن الصلاح
|
تقی الدین ابو عمرو عثمانؒ بن الصلاحؒ
|
۶۴۹
|
مصباح الظلام
|
حسینؒ بن علی الحصنی الحصکفیؒ
|
۹۱۷
|
الدر فی مصطلح اہل الاثر
|
یونس الاثری الرشیدیؒ
|
۱۰۲۰
|
بغنیۃ الطالبین بمعرفۃ اصطلاح المحدثین
|
عبد الرؤفؒ بن تاج الدین المنادیؒ
|
۱۰۳۱
|
اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر
|
عبد الرؤفؒ بن تاج الدین المنادیؒ |
۱۰۳۱
|
التیقید والایضاح
|
زین الدین عبد الرحیم العراقی ؒ
|
۸۰۶
|
فتح المغیث
|
زین الدین عبد الرحیم العراقی ؒ |
۸۰۶ |
النیۃ نظم الدر فی علم الاثر
|
زین الدین عبد الرحیم العراقی ؒ |
۸۰۶ |
الافصاح بتکمیل النکت علیٰ ابن الصلاح
|
حافظ ابو الفضل احمدؒ بن علیؒ بن حجرؒ
|
۸۵۲
|
نخبۃ الفکر
|
حافظ ابو الفضل احمدؒ بن علیؒ بن حجرؒ |
۸۵۲ |
نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر
|
حافظ ابو الفضل احمدؒ بن علیؒ بن حجرؒ |
۸۵۲ |
الباعث الحثیث
|
ابو الفداء عماد الدین اسماعیلؒ بن کثیرؒ
|
۷۷۴
|
النہل الروی فی حدیث النبوی
|
بدر الدینؒ بن جماعت الکنانیؒ
|
۷۳۳
|
زوال السرّح شرح المنظومۃ ابن فرعؒ
|
بدر الدینؒ بن جماعت الکنانیؒ |
۷۳۳
|
النہج السومی فی شرح النہل الروی
|
عز الدین الکنانیؒ
|
۸۱۹
|
محاسن الاصطلاح فی تضمین نکت ابن الصلاح
|
سراج الدین ابو حفص عمرؒ بن رسلان البلقینی ؒ
|
۸۰۵
|
تقریب الارشاد
|
محی الدینؒ بن شرف النوویؒ
|
۶۷۶
|
نکت علی ابن الصلاح
|
بدر الدین محمد بہادر الزرکشیؒ
|
۷۹۴
|
نکت الوفیۃ شرح الالفیۃ
|
برہان الدین ابراہیم الینفاعیؒ
|
۸۵۵
|
شرح الالفیۃ
|
شیخ علیؒ بن احمدؒ بن مکرم الصعیدیؒ
|
۱۱۸۹
|
فتح الباقی شرح الفیۃ العراقی
|
قاضی ابو یحیٰی زکریاؒبن محمد الانصاری المصری الشافعیؒ
|
۹۲۸
|
قضاء الوطر من نزہۃ النظر
|
ابو الامداد ابراہیم اللقانی المالکیؒ
|
۱۰۴۱
|
شرح نخبۃ الفکر
|
علامہ سری الدینؒ بن الصائغ ؒ
|
۱۰۶۶
|
نظم النخبۃ
|
شہاب الدین احمدؒ بن محمد الطوفیؒ
|
۸۹۳
|
شرح نخبۃ الفکر
|
کمال الدین الاسکندری المالکیؒ
|
۸۲۱
|
لقط الدرر
|
عبد اللہؒ بن حسین السمین العددیؒ (سنِ تالیف)
|
۱۳۰۹
|
شرح التقریب
|
برہان الدین القباقبی الحلبی المقدسیؒ
|
۸۵۱
|
مصطلاحات اہل الاثر
|
علیؒ بن السلطان الہروی القاری الحنفیؒ
|
۱۰۱۴
|
شرح شرح نخبۃ الفکر
|
کمال الدین محمدؒ بن محمدؒ ابن ابی الشریف المقدسیؒ
|
۹۰۵
|
بہجۃ النظر شرح شرح نخبۃ الفکر
|
ابو الحسن محمد صادقؒ بن عبد الہادی السندی الحنفیؒ
|
۱۱۳۸
|
العالی الرتبۃ فی شرح نظم النخبۃ
|
ابو العباس احمدؒ بن محمد الشمنی الحنفیؒ
|
۸۷۲
|
فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث
|
علامہ شمس الدین محمدؒ بن عبد الرحمٰن السخاویؒ
|
۹۰۲
|
سلک الدرر
|
محمد رضی الدین ابو الفضل الغزیؒ
|
۹۳۵
|
توضیح الافکار
|
محمدؒ بن اسماعیل الامیر الیمانیؒ
|
۸۴۰
|
عقد الدرر فی نظم نخبۃ الفکر
|
شیخ الاسلام ابی محمد عبد القادر القاضیؒ
|
۱۱۱۶
|
حاشیۂ شرح الفیۃ
|
برہان الدین عمرؒ بن ابراہیم البقاعیؒ
|
۸۸۵
|
کتاب التذکرۃ
|
سراج الدین عمرؒ بن الملقنؒ
|
۸۹۳
|
شرح شرح الفیۃ الحدیث
|
زین الدین عبد الرحمٰن بن ابی بکر العینیؒ
|
۸۹۳
|
شرح شرح الفیۃ الحدیث
|
ابراہیمؒ بن محمد الحلبیؒ
|
۹۵۵
|
| شرح شرح الفیۃ الحدیث |
ابو الفداء اسماعیلؒ بن جماعۃؒ
|
۸۶۱
|
کوثر النبی
|
عبد العزیز فرہارویؒ صاحب النبراس
|
۱۲۳۹
|
قواعد التحدیث
|
جمال الدین القاسمیؒ
|
۱۳۳۲
|
توجیہ النظر الٰی اصول الاثر
|
العلامہ طاہرؒ بن احمد الجزائریؒ (سن تالیف)
|
۱۳۲۸
|
ان کے علاوہ محمدؒ بن النفلوطیؒ (المتوفٰی ۷۰۲ھ) اور علامہ ابن الجریریؒ (المتوفٰی ۸۳۳ھ) وغیرہ بے شمار حضرات نے اصولِ حدیث کے سلسلہ میں مختصر اور مطول کتابیں تصنیف کی ہیں جن کا احصار و شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جامع بیان العلم و فضلہ لابن عبد البرؒ (المتوفٰی ۴۶۳ھ)۔ شروط الائمۃ الخمسۃ للحازمیؒ (المتوفٰی۵۸۴ھ)۔ مقدمۂ فتح الباری لحافظ لابن حجرؒ۔ مقدمۂ عمدۃ القاری للعلامہ بدر الدین محمودؒ بن احمد العینی الحنفیؒ (المتوفٰی ۸۵۵ھ)۔ مقدمۂ شرح مسلم للنوویؒ۔ مقدمۂ نصب الرأیہ للعلامہ الزاہد الکوثری الحنفیؒ (المتوفٰی ۱۳۷۲ھ)۔ مقدمۂ فتح الملہم، مولانا شبیر احمد عثمانیؒ (المتوفٰی ۱۳۶۹ھ)۔ مقدمۂ تحفۃ الاحوذی، مولانا مبارکپوریؒ (المتوفٰی ۱۳۵۳ھ)۔ مقدمۂ اعلاء السنن، مولانا ظفر احمد عثمانیؒ (المتوفٰی ۱۳۹۴ھ)۔ مقدمہ معارف السنن، مولانا بنوریؒ (المتوفٰی ۱۳۹۷ھ)۔ مقدمہ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث للشیخ عبد الحق محدث دہلویؒ (المتوفٰی ۱۰۵۲ھ)۔ الحطۃ فی ذکر الصحاح الستۃ للنواب صدیق حسن خانؒ۔ عجالۂ نافعہ و بستان المحدثین لشاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ (المتوفٰی ۱۲۳۹ھ)۔ مقدمہ حاشیۂ بخاری، مولانا احمد علی سہارنپوریؒ (المتوفٰی ۱۲۹۷ھ)۔ مقدمۂ بذل الجہود، مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ (المتوفٰی ۱۳۴۶ھ)۔ مقدمہ لامع الدراری، مولانا محمد یحیٰی کاندھلویؒ (المتوفٰی ۱۳۳۴ھ)۔ مقدمۂ اما فی الاحبار، مولانا محمد یوسف صاحبؒ (المتوفٰی ۱۳۸۴ھ)۔ مقدمۂ ترجمان السنۃ، مولانا محمد بدر عالم مدنیؒ (المتوفٰی ۱۳۸۵ھ)۔ مقدمہ انوار الباری شرح البخاری، مولانا سید احمد رضا بجنوری۔ ماتمس الیہ الحاجۃ، مولانا عبد الرشید نعمانی وغیرہ کتابیں اصولِ حدیث، اقسامِ حدیث، عللِ حدیث، اور احوالِ رجال وغیرہا اصولی بحثوں پر خوب روشنی ڈالتی ہیں۔
الغرض اصولِ حدیث کے پیشِ نظر جعل سازوں کے لیے جعلی حدیثیں تراش تراش کر عوام کے سامنے پیش کرنے کا چور دروازہ ہی بالکل بند ہو جاتا ہے اور بفضلہ تعالٰی تمام احادیث کو کتبِ حدیث میں ضبط کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت امام بیہقیؒ (الحافظ الجلیل ابوبکر احمدؒ بن الحسینؒ، المتوفٰی ۴۵۸ھ) کا یہ مقولہ ایک خالص حقیقت معلوم ہوتا ہے ’’من جاء الیوم بحدیث لا یوجد عند الجمیع لا یقبل منہ‘‘ (مقدمۂ ابن الصلاح ص ۱۰۰، فتح المغیث ص ۹۶، توجیہ النظر ص ۲۱۹)۔ یعنی جو شخص آج اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے جو محدثین کرامؒ کی کتابوں میں موجود نہیں تو وہ حدیث مقبول نہ ہو گی۔ لیکن صد افسوس ہے کہ منکرینِ حدیث کی طرح جعل سازوں پر احتیاط کے ایسے طرق اور سامانِ ہدایت کی موجودگی میں بھی کچھ اثر نہیں، کوئی نصیحت اور فہمائش ان کو کام نہیں دیتی، کتنا ہی سمجھاؤ پتھر پر جونک نہیں لگتی۔
ضعیف احادیث اور ضعیف روات پر مشتمل کتب
حضرات محدثین کرامؒ نے احادیث کو اصلی شکل میں محفوظ رکھنے کے لیے ضعیف روایات اور ضعیف روات کے بارے میں الگ تصانیف لکھی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ان سے استفادہ کر کے ضعیف احادیث اور ضعیف روات کی روایات سے اجتناب کر سکیں۔ اس سلسلہ کی کتب بھی بے شمار ہیں، چند مشہور یہ ہیں:
| نام کتاب |
نام مصنف |
تاریخ وفات |
کتاب الضعفاء الکبیر والصغیر
|
امام بخاریؒ
|
۲۵۶ھ
|
کتاب الضعفاء والمتروکین
|
امام نسائیؒ
|
۳۰۳ھ
|
کتاب الضعفاء
|
ابو اسحاق الجوزجانیؒ
|
۲۵۹ھ
|
| کتاب الضعفاء |
ابو جعفر العقیلیؒ
|
۳۲۳ھ
|
| کتاب الضعفاء |
ابو نعیم استرآبادیؒ
|
۳۲۳ھ
|
| کتاب الضعفاء |
ابن عدیؒ (بارہ جلدوں میں)
|
۳۶۵ھ
|
| کتاب الضعفاء |
ابو عبد اللہ البرقیؒ
|
۲۴۹ھ
|
| کتاب الضعفاء |
ابو الفتح محمدؒ بن الحسین الازدیؒ
|
۳۷۴ھ
|
عللِ حدیث
اسانید اور متونِ حدیث میں بعض روات سے جو اغلاط و اوہام سرزد ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کے سلسلہ میں بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ حضرت امام بخاریؒ اور حضرت امام مسلمؒ اور حضرت امام ترمذیؒ کی علل کبیر و صغیر، کتاب العلل للدارقطنیؒ، کتاب العلل لابن ابی حاتمؒ، علل متناہیہ لابن الجوزیؒ وغیرہ کتابیں اس سلسلہ میں کافی مشہور اور علماء فن کے نزدیک معروف ہیں۔
کتبِ موضوعات
حضرات محدثین کرامؒ نے اپنی دانست اور صوابدید کے مطابق جعلی، موضوع اور من گھڑت روایات کو الگ کر کے کتب تصنیف کی ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے امت گمراہ نہ ہو جائے، اور سنتِ صحیحہ سے ہٹ اور کٹ کر خودساختہ راستوں پر نہ چل نکلے۔ اس سلسلے کی مشہور کتابیں یہ ہیں:
| نام کتاب |
نام مصنف |
تاریخ وفات |
موضوعات
|
ابن الجوزیؒ
|
۵۹۷ھ
|
مختصر الموضوعات
|
امام سفارینیؒ
|
|
رسالتان فی الموضوعات
|
رضی الدین صغانیؒ
|
۶۵۰ھ
|
الفواعد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ
|
شیخ ابی عبد اللہ محمد شامیؒ
|
|
| الفواعد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ |
القاضی شوکانیؒ
|
۱۲۵۵ھ
|
الموضوعات الصریحۃ
|
عمرؒ بن بدرؒ
|
|
کتاب المغنی
|
حافظ ضیاء الدین موصلیؒ
|
۶۲۳ھ
|
کتاب الاباطیل
|
ابو عبد اللہ الحسین ہمدانیؒ
|
۵۴۳ھ
|
الؤلو المرصوع
|
محمدؒ بن خلیل قادقچیؒ
|
۱۳۰۵ھ
|
الکشف الالہٰی
|
محمد سندوسیؒ
|
۱۱۷۷ھ
|
اللالی المضوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ
|
جلال الدین سیوطیؒ
|
۹۱۱ھ
|
موضوعاتِ کبیرہ
|
ملا علی ن القاریؒ
|
۱۰۱۴ھ
|
الموضوع فی الحدیث الموضوع
|
ملا علی ن القاریؒ |
۱۰۱۴ھ |
تذکرۃ الموضوعات
|
علامہ محمدؒ بن طاہر الفتنی الحنفیؒ
|
۹۸۷ھ
|
قانون الموضوعات
|
علامہ محمدؒ بن طاہر الفتنی الحنفیؒ |
۹۸۷ھ |
الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعۃ
|
مولانا عبد الحی لکھنویؒ
|
۱۳۰۴ھ
|
کشف الحثیث عمن رمی بوضع الحدیث
|
برہان الدین ابو الوفاء سبط ابن العجمیؒ
|
۸۴۱ھ
|
تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعۃ
|
علامہ ابو الحسن علیؒ بن محمدؒ بن عراقؒ
|
|
ذخائر المواریث فی الدلالۃ علٰی مواضع الحدیث
|
علامہ عبد الغنیؒ بن جماعۃ النابلسیؒ
|
۱۱۴۳ھ
|
شانِ نزولِ حدیث
کسی بھی عقل مند کو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ہر متکلم کی بات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی اپنے مقام پر کوئی نہ کوئی سبب ضرور تھا۔ اس سلسلہ میں علامہ ابراہیمؒ بن محمدؒ بن کمال الدین الشہیر بابن حمزۃ الحسینی الحنفیؒ (المتوفٰی ۱۱۳۰ھ) کی کتاب ’’البیان والتعریف فی سبب درود الحدیث‘‘ تین جلدوں میں طبع ہو کر منصۂ شہود پر آ چکی ہے۔ جس میں پہلے حدیث کا ایک حصہ نقل کر کے کتبِ حدیث سے اس کا ماخذ بتاتے ہیں، پھر اس کی تصحیح اور تضعیف کا لحاظ کرتے ہیں، اور پھر اس کا سببِ درود بیان کرتے ہیں۔
بخاری کی احادیث کی تلاش
اہلِ علم کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ ’’فقہ البخاری فی الابواب والتراجم‘‘ حضرت امام بخاریؒ ایک ایک حدیث کو کلاً یا بعضاً مختلف ابواب میں نقل کرتے ہیں۔ بسا اوقات بخاری کی احادیث کی تلاش میں خاصی دقت پیش آتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا عبد العزیز سہالوی ثم گوجرانوالویؒ (المتوفٰی ۱۳۵۹ھ) نے ’’نبراس الساری فی اطراف البخاری‘‘ لکھ کر امت پر احسان کیا ہے جس سے آسانی کے ساتھ بیک وقت بخاری میں ایک ہی حدیث متعدد ابواب میں مل جاتی ہے۔
معانی الاحادیث
کتبِ حدیث میں بغیر مسند دارمی کے اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں بظاہر مختلف اور متضاد قسم کی حدیثیں نہ آتی ہوں۔ ان کی جمع و تطبیق کے سلسلہ میں حضرت امام شافعیؒ کی اختلاف الحدیث، حضرت امام طحاویؒ (امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامۃؒ) جو الامام العلامۃ اور الحافظ تھے (تذکرہ ج ۳ ص ۲۸) اور وہ علماء کی سیرت اور ان کی اخبار کو سب سے زیادہ جانتے تھے اور حضرات فقہاء کرامؒ کے تمام مذاہب کو جانتے تھے ’’کان عالما مجمیع مذاھب الفقہاء‘‘ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۷۸)، علامہ ابن حزم ابو محمد علیؒ بن احمدؒ (المتوفٰی ۳۲۱ھ) جو الامام العلامۃ الحافظ الفقیہ اور المجتہد تھے، امام طحاویؒ کی کتابوں کو صحت میں بخاری و مسلم وغیرہ کے ہم پلہ مانتے ہیں (تذکرہ ج ۳ ص ۳۲۸) کی شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار، امام ابن قتیبہؒ (المتوفٰی ۲۷۶ھ) کی مختلف الحدیث، امام ابن عبد البرؒ کی تمہید اور اس کا ملخص استدکار اور کتبِ شروحِ حدیث اس قدر ہیں کہ ان کا آسانی سے شمار و احصار نہیں کیا جا سکتا۔
الغرض امتِ مرحومہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی حفاظت اور امت کے لیے ان کی تسہیل و تشریح کے لیے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جن سے زیادہ محتاط اور معقول طریقے انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ اور یہ کوشش اور کاوش محض احادیث کو سندًا و متناً و مرادًا محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ مگر منکرینِ حدیث کو ان حقائق سے کیا واسطہ، وہ تو ان کاوشوں کو بازیچۂ اطفال سے تعبیر کریں گے
زمامِ کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو تو کیا
طریقِ کوہکن میں بھی وہی حیلے ہیں پرویزی
لغات الحدیث
اس فن میں متعدد کتابیں ہیں جن میں النہایہ فی غریب الحدیث لابن الاثیر (مجدد الدین ابی السعادات المبارکؒ بن محمد الجزریؒ المتوفٰی ۶۰۶ھ)۔ الفائق، علامہ جار اللہ محمود بن عمر الزمحشری (المتوفٰی ۵۳۸ھ)۔ المغرب للعلامہ ابی الفتح ناصر الدینؒ بن عبد السید الحنفی الخوارزمیؒ (المتوفٰی ۵۳۵ھ)۔ اور مجمع البحار للعالمۃ محمدؒ بن طاہرؒ وغیرہ معروف و مشہور کتابیں ہیں۔
سرمایہ داری اور اسلامی نظامِ معیشت
شیخ التفسیر مولانا صوفی عبد الحمید سواتیؒ
حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پر ہرقل قیصرِ روم کو بھی خط لکھا تھا۔ جب یہ خط قیصر کو پیش ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی شخص مل جائے تو حاضر کیا جائے۔ ان دنوں غزہ میں ابوسفیان کی قیادت میں قریشِ مکہ کا ایک تجارتی قافلہ مقیم تھا۔ چنانچہ ابوسفیان کو ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا اور ہرقل نے ان سے حضور علیہ السلام کے متعلق مختلف سوال کیے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جس مدعی نبوت کا خط مجھے پہنچا ہے اس کے اولین متبعین کمزور لوگ ہیں یا با اثر شخصیتیں؟ تو ابوسفیان نے کہا کہ نادار اور کمزور لوگ ہیں۔ اس پر ہرقل پکار اٹھا کہ ابتدا میں نبیوں کے پیروکار ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں، بڑے لوگ اس وقت ایمان لاتے ہیں جب ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا۔ ہرقل کا یہ مقولہ سابقہ کتابوں کی تعلیم سے بھی معلوم ہوتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھا دی ہے کہ مال و دولت یا جاہ و منصب پر اترانا غلط بات، اصل میں مدارِ عزت ایمان ہے نہ کہ جاہ و حشمت، اللہ کے ہاں باعزت وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری جس کا شیوہ ہے۔ اور یہ صفات ان غربا و مساکین میں پائی جاتی ہیں مگر مالدار اور چوہدری قسم کے لوگ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا، اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو ناانصافوں میں شامل ہو جائیں گے۔
فرمایا ’’وَکَذٰلِکَ فَتَنَّا بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ‘‘ اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض سے۔ یعنی بعض آدمیوں کو ہم نے مال و دولت یا جاہ و حکومت دے کر آزمایا کہ یہ اپنے ماتحتوں یا کمتر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان کو حقیر سمجھ کر حقارت آمیز سلوک کرتے ہیں یا ان کا احترام کرتے ہیں اور خوشدلی سے پیش آتے ہیں۔
اسی طرح مساکین کو عسرت میں مبتلا کر کے آزمایا ہے۔ سورہ فرقان میں موجود ہے ’’وَجَعَلْنَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَۃً‘‘ ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے ’’اَتَصْبِرُوْنَ‘‘ کیا تم صبر کرتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ غرباء کو غربت میں مبتلا کر کے آزمایا ہے کہ آیا یہ امراء کی امارت دیکھنے کے باوجود صبر کرتے ہیں؟ ’’وَکَانَ رَبُّکَ بَصِیْرًا‘‘ تیرا رب تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔
وہ امیر کو دولت دے کر آزماتا ہے کہ یہ مساکین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور غریب کو غربت دے کر آزماتا ہے کہ یہ کس حد تک صبر کرتا ہے۔ مگر مقامِ افسوس ہے کہ اس آزمائش میں دونوں طبقے ناکام رہے ہیں، نہ تو دولت مند غرباء کا خیال رکھتے ہیں اور نہ مساکین صبر سے کام لیتے ہیں۔
روس میں ۱۹۱۷ء کا انقلاب اسی امیر غریب کے سوال پر ہی آیا تھا جس کی بھینٹ تین کروڑ آدمی چڑھ گئے۔ امراء نے غرباء پر مظالم توڑے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غریبوں نے تحریک چلائی۔ دونوں گروہ بے دین تھے۔ غریبوں نے امیروں کو مردار کتوں کی طرح گھسیٹا۔ یہ غریبوں کو حقیر سمجھنے کا شاخسانہ تھا۔ نہ امیروں نے حقوق ادا کیے نہ غریبوں نے صبر کیا۔ جس کا نتیجہ کشت و خون کی صورت میں نکلا۔ شیخ سعدیؒ نے گلستان میں ایک ایسا عمدہ فقرہ کہا ہے جس کے متعلق لوگوں نے کہا کہ ہماری ساری کتابوں کے بدلے یہ ایک فقرہ ہمیں دے دیں۔ کہتے ہیں:
’’خواہندۂ مغربی در صف بزازان حلب میگفت اے خداوندِ نعمت اگر شمارا انصاف بود و مارا قناعت رسم سوال از جہاں برخاستے۔‘‘
’’ملک کے مغرب میں ایک محتاج نے بزازوں کی صف میں کھڑے ہو کر کہا، اے دولت کے مالکو! اگر تم میں انصاف اور ہم میں قناعت ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی سوال نہ کرتا یعنی سوال کی رسم ہی برخواست ہو جاتی۔‘‘
ہم دونوں مجرم ہیں، تم میں سخاوت نہیں ہے اور ہم قناعت سے محروم ہیں، دولت کے ہوتے ہوئے تم مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے اور ہم صبر سے عاری ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا مصائب کا شکار بنی ہوئی ہے۔
یاد رکھنا چاہیئے کہ اسلام نے اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے اس دولت کو لعنت کے برابر کہا ہے جس میں سے غریبوں کے حقوق نہ ادا کیے جائیں۔ ایسی دولت مندی باعثِ وبال ہے۔ ہاں اگر اپنے مال سے تمام فرضی، واجبی حقوق ادا کرتا ہے تو پھر یہ دولت جائز ہے۔ اگر حلت و حرمت کا امتیاز ختم ہو چکا ہے تو پھر یہ سرمایہ داری (Capitalism) ہے، اس کا حامی سرمایہ پرست ہے۔
اور دوسری طرف نفرت اور عداوت کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ سرمایہ داروں کے پاس سرمایہ کیوں ہے؟ خواہ اس نے جائز ذرائع سے ہی کیوں نہ حاصل کیا ہو اور وہ تمام حقوق بھی کیوں نہ ادا کرتا ہو، مگر محض صاحبِ مال و دولت ہونا ہی گردن زدنی سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ یہ لوگ نہ صرف سرمایہ داری کے خلاف ہوتے ہیں بلکہ آگے چل کر مذہب کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے مذہب کی آڑ لے رکھی ہے۔
سوشلسٹ ملکوں میں یہی کچھ ہوا ہے۔ پہلے سرمایہ داروں کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر آہستہ آہستہ مذہب کو ہی خیرباد کہہ دیا۔ ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ اکثر و بیشتر اقتدار پسندوں، سرمایہ داروں اور ملوک نے مذہب کو غلط استعمال کیا ہے۔ البتہ کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اورنگزیب عالمگیرؒ بھی تو بادشاہ تھے، سلطان ناصر الدین التمشؒ بھی اسی سرزمین پر مسندِ اقتدار پر رہا ہے۔ اس کے پاس کابل سے لے کر برما تک حکومت تھی مگر دل میں خوفِ خدا رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ جیسے بلند پایہ لوگ بھی تو ہوئے ہیں جن پر اقتدار کا نشہ غالب نہیں آیا اور جنہوں نے مستحقین کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن یہ مذہب کا غلط استعمال تھا جس کی وجہ سے ملحدوں کو مذہب کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ غرضیکہ یہ دونوں گروہ لعنتی ہیں۔
اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ملک میں صرف حلال و حرام کی پابندی پوری طرح نافذ کر دی جائے تو لوگوں کو سکون حاصل ہو جائے۔ جو مال حرام ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا مصرف بھی حرام اور من مانے طریقے پر کیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ دولت حاصل کیسے کی اور اسے خرچ کس چیز پر کر رہے ہو۔ فضول خرچی قطعاً حرام اور تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے سرمایہ داری اور اشتراکی نظامِ معیشت دونوں ملعون ہیں۔ صرف اسلام کا نظام ہی درست ہے جو دولت مندی کی حوصلہ افزائی اس وقت کرتا جب وہ جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو اور اس میں سے تمام حقوق ادا کیے گئے ہوں۔ اگر جائز و ناجائز کی تمیز روا نہیں رکھی تو یہی سرمایہ داری ہے جو ملعون ہے۔
انبیاءؑ کے حق میں ذنب و ضلال کا مفہوم
مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ
اہلِ اسلام کے نزدیک انبیاءؑ کی عصمت عقلاً اور نقلاً ثابت ہے اور اس کی عقلی اور نقلی دلیلیں علم کلام کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ اور یہ بات بھی ان کے نزدیک ضروری اور مدلل ہے کہ جو لفظ لغت سے شرع میں منقول ہوئے ہیں مثلاً صلوٰۃ اور زکوٰۃ اور حج وغیرہا، جب خدا اور رسول کے کلام میں مستعمل ہوتے ہیں تو وہ ان کے معانی شرعیہ مراد لیتے ہیں۔ اور جب تک کوئی عقلی یا نقلی دلیل قطعی ایسی نہ ہو کہ معنے شرعی کے مراد لینے سے منع کرے تب تک وہی معانی مراد لیتے ہیں۔
ذنب
چنانچہ لفظ ذنب بھی شریعت میں جہاں کہیں انبیاء علیہم السلام کے حق میں واقع ہوا ہے تو زلّہ اور ترک اولٰی کے معنی میں آیا ہے۔ اور زل اس کو کہتے ہیں کہ شخصِ معصوم عبادت یا کسی امرِ مباح کے کرنے کا قصد کرتا ہے لیکن اس سبب سے کہ اس عبادت یا امرِ مباح کے ساتھ کوئی گناہ ملا ہوا ہوتا ہے تو بغیر قصد کے اس میں گر پڑتا ہے۔ جیسے راہ کا چلنے والا کبھی بغیر قصد کے پتھر سے ٹھوکر کھا کر یا کیچڑ کے سبب پھسل کر گر جاتا ہے، لیکن قصد راہ کا چلنا تھا نہ گر پڑنا۔ اور نبوت کے منصب کا لحاظ کر کے قول ’’حسنات الابرار سیات المقربین‘‘ کے موافق نبی کے اس ترک اولٰی پر ذنب کا اطلاق ہوتا ہے۔
ضلال
اور لفظِ ضلال قرآن کے اندر جہاں کفار کی مذمت میں واقع ہوتا ہے تو حق کی راہ سے گمراہ ہونے کے معنے میں آتا ہے، اور اگر ان کی مذمت میں نہیں ہوتا تو کہیں راہ بھولنے کے معنے میں آتا ہے جیسے سورہ قلم کی چھبیسویں آیت کے اندر ہے ’’فَلَمَّا رَاَؤْھَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ‘‘ یعنی پھر جب اس کو (یعنی باغ کو) دیکھا، بولے ہم راہ بھولے۔ اور کہیں ایسے رَل مِل جانے اور مخلوط ہو جانے کے معنی میں آتا ہے کہ جس میں تمیز نہ ہو سکے، جیسے سورہ سجدہ کی آیت میں ہے ’’وَقَالُوْا اَئِذَا ضَلَلْنَا فِی الْاَرْضِ اَئِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ‘‘ یعنی اور کہتے ہیں (قیامت کے منکر) کیا جب ہم رَل مِل گئے زمین (کی مٹی) میں کیا ہم کو نیا بننا ہے؟ اور ۔۔ بولتے ہیں ’’ضل الماء فی اللبن‘‘ یعنی پانی دودھ میں ایسا رَل مِل گیا کہ اس کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ اور کہیں عشق اور محبت کی زیادتی کے سبب چوکنے کے معنے میں آتا ہے جیسا کہ سورہ یوسف کی آٹھویں آیت میں حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا قول ہے ’’اِنَّ اَبَانَا لَفِیْ ضَلَالٍ مُبِیْنٍ‘‘ یعنی البتہ ہمارا باپ صریح چوک میں ہے۔ یعنے یوسف اور اس کے بھائیوں سے زیادتی عشق اور محبت کے سبب۔ اور اسی سورہ کی تیسویں آیت میں مصر کی عورتوں کا زلیخا کے حق میں یہ قول ہے ’’اِنَّا لَنَرٰھَا فِیْ ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ‘‘ یعنی ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح بہکی ہوئی۔ یعنی یوسف کے عشق کے غلبہ کے سبب سے۔ اور اسی سورہ کی پچاسویں آیت کے اندر لوگوں کا قول حضرت یعقوبؑ کے حق میں ہے ’’قَالُوْا تَاللّٰہِ اِنَّکَ لَفِیْ ضَلَالِکَ الْقَدِیْمِ‘‘ یعنی لوگ بولے اللہ کی قسم تو اپنے اسی قدیم بہکنے میں ہے۔ یعنی یوسف کے عشق اور محبت کی زیادتی کے سبب ہے۔ اور کہیں اللہ کے حکموں سے واقف نہ ہونے کے معنے میں آتا ہے جیسے سورہ شعراء کی بیسویں آیت میں قول حضرت موسٰیؑ کا یوں منقول ہوا ہے ’’فَعَلْتُھَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّیْنَ‘‘ یعنی کیا تو ہے میں نے وہ جبکہ تھا اس وقت نادانوں سے۔
پس اس آیت میں لفظ ضالین بمعنی جاہلین کے ہے اور اس معنے کو یہ بات بھی مؤید ہے کہ بعض قراءت میں ضالین کے لفظ کی بجائے جاہلین کا لفظ واقع ہے، اور اسی طرح ضلال کا لفظ یا جو اس سے مشتق ہے قرآن میں جہاں اور جگہ بھی واقع ہوا ہے اس مقام کے مناسب لیا جاتا ہے۔ اور سب جگہ کفر اور گمرہی کے معنی میں لینا محض گمراہی ہے۔ اور مسلمانوں کی شریعت سے واقف ہو کر یعقوب اور موسٰی علیہما السلام کے حق میں بمعنے کفر اور گمراہی کے کافر اور گمراہ کے سوا اور شخص نہیں کہہ سکتا، اور ایسا ہی انبیاء کے حق میں سمجھنا چاہیئے۔ اور عرب اس درخت کو جو جنگل میں اکیلا ہوتا ہے ضالّہ کہتے ہیں۔
ہمارے دینی مدارس — توقعات، ذمہ داریاں اور مایوسی
مولانا ابوعمار زاہد الراشدی
ہمارے معاشرہ میں دینی مدارس کے کردار کے مثبت پہلو کے بارے میں کچھ گزارشات ’’الشریعہ‘‘ کے گزشتہ سے پیوستہ شمارے میں پیش کی جا چکی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ فرنگی اقتدار کے تسلط، مغربی تہذیب و ثقافت کی یلغار اور صلیبی عقائد و تعلیم کی بالجبر ترویج کے دور میں یہ مدارس ملی غیرت اور دینی حمیت کا عنوان بن کر سامنے آئے اور انہوں نے انتہائی بے سروسامانی کے عالم میں سیاست، تعلیم، معاشرت، عقائد اور تہذیب و ثقافت کے محاذوں پر فرنگی سازشوں کا جرأتمندانہ مقابلہ کر کے برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش کو اسپین بننے سے بچا لیا۔ اور یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج اس خطۂ زمین میں مذہب کے ساتھ وابستگی اور اسلام کے ساتھ وفاداری کے جن مظاہر نے کفر کی پوری دنیا کو لرزہ براندام کر رکھا ہے، عالمِ اسباب میں اس کا باعث صرف اور صرف یہ دینی مدارس ہیں۔ لیکن مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کے دوسرے رخ پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے اور اربابِ فہم و دانش کی ان توقعات اور امیدوں کا مرثیہ بھی پڑھ لیا جائے جن کا خون ناحق ہمارے دینی مدارس کی اجتماعی قیادت کی گردن پر ہے۔ تفصیلات و فروعات تک گفتگو کا دائرہ وسیع کرنے کی بجائے ہم اپنی گزارشات کو صرف دو سوالات کے حوالے سے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔
- جدید مغربی فلسفۂ حیات کے اثرات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے دینی مدارس کا کردار کیا ہے؟
- اور مسلم معاشرے میں نفاذ اسلام کے ناگزیر علمی و فکری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان مدارس کا نظامِ کار اور حکمتِ عملی کیا ہے؟
ایک دور تھا جب یونانی فلسفہ نے عالم اسلام پر یلغار کی تھی اور عقائد و افکار کی دنیا میں بحث و تمحیص کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ اگر اس وقت عالمِ اسلام کے تعلیمی مراکز اور اہلِ علم یونانی فلسفہ کی اس یلغار کو وقتی طوفان سمجھ کر نظرانداز کر دیتے اور اپنے کان اور منہ لپیٹ کر اس کے گزر جانے کا انتظار کرتے رہتے تو اسلامی علوم و عقائد کا پورا ڈھانچہ فلسفۂ یونان کی حشر سامانیوں کی نذر ہو جاتا۔ لیکن علمائے اسلام نے اس دو رمیں ایسا نہیں کیا بلکہ یونانی فلسفہ کے اس چیلنج کو قبول کر کے خود اس کی زبان میں اسلامی عقائد و افکار کو اس انداز سے پیش کیا کہ یونانی فلسفہ کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارۂ کار نہ رہا اور اس کے بپا کیے ہوئے فکری اور نظریاتی معرکوں کے تذکرے آج رازیؒ، غزالیؒ، ابن رشدؒ اور ابن تیمیہؒ کی تصنیفات میں یادگار کے طور پر باقی رہ گئے ہیں۔
یورپ کے جدید فلسفۂ حیات کی یلغار بھی یونانی فلسفہ کے حملہ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہ فلسفۂ حیات جس نے انقلابِ فرانس کے ساتھ اپنا وجود تسلیم کرایا اور پھر یورپ کے صنعتی انقلاب کے زیر سایہ اپنا دائرہ وسیع کرتے ہوئے آج دنیا کے اکثر و بیشتر حصہ کو لپیٹ میں لے چکا ہے، خود کو انسانی زندگی کے ایک ہمہ گیر فلسفہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور انسان کی پیدائش کےمقصد سے لے کر انسانی معاشرت کے تقاضوں اور مابعد الطبعیات کی وسعتوں تک کو زیر بحث لاتا ہے۔ ڈارون، فرائیڈ، نطشے اور دیگر مغربی فلاسفروں اور سائنس دانوں کی گزشتہ دو صدیوں پر محیط فکری کاوشوں اور نظریاتی مباحث کا خلاصہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کلیسا کی بدکرداریوں اور مظالم کے ردعمل کے طور پر جنم لینے والے اس فلسفہ کو یورپ نے ایک مکمل فلسفۂ حیات کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں موجود اسلام سمیت تمام فلسفہ ہائے حیات کو مکمل شکست سے دوچار کر کے فنا کے گھاٹ اتارنے کے درپے ہے۔
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یورپ کی اس فکری یلغار کی ماہیت اور مقاصد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اسے محض اقتصادی اور سیاسی بالادستی کا جنون سمجھ کر اس انداز میں اس کا سامنا کرتے رہے اور اس کی فکری اور اعتقادی پہلوؤں کو مکمل طور پر نظرانداز کر دیا۔ یونانی فلسفہ کے در آنے سے ہمارے ہاں عقائد کے نئے مباحث چھڑ گئے تھے جنہیں علمائے اسلام نے اپنے فکری اور علمی مباحث میں سمو دیا اور ہمارے عقائد کی بیشتر کتابیں ان مباحث سے بھرپور ہیں۔ حتیٰ کہ دینی مدارس کے نصاب میں آج کے طلبہ کو بھی عقائد کے حوالے سے انہی مباحث سے روشناس کرایا جاتا ہے جو یونانی فلسفہ کی پیداوار ہیں اور جن میں سے زیادہ تر کا آج کے نئے فکری اور اعتقادی تقاضوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن جو اعتقادی اور فکری و تہذیبی مباحث یورپ کے فلسفۂ حیات نے چھیڑے ہیں، نہ ہماری عقائد کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہم طلبہ کو ان مباحث کی ہوا ہی لگنے دیتے ہیں۔
ڈارون کا نظریۂ ارتقا، انسان کے مقصدِ وجود میں کششِ جنسی کی محوری حیثیت کے بارے میں فرائیڈ کے تصورات، اجتماعی زندگی سے مذہب کی مکمل لاتعلقی اور غیر محدود فکری آزادی کا نعرہ آخر اعتقادی مباحث نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور کیا انہی افکار و نظریات کا شکار ہو کر مسلمان کہلانے والوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کے اجتماعی کردار سے منکر یا کم از کم مذبذب نہیں ہو چکی ہے؟ اس اعتقادی فتنہ کی روک تھام کے لیے ہمارے دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ ہمارے نصاب میں تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد کی کون سی کتاب میں یہ مباحث شامل ہیں او رہم اپنے طلبہ کو ان مباحث سے روشناس کرانے اور انہیں ان کے جواب کی خاطر تیار کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
یہ وقت کا ایک اہم سوال اور دینی مدارس کی اجتماعی قیادت پر مسلم معاشرہ اور نئی نسل کا ایک قرض ہے جس کا سامنا کیے بغیر ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ فروعی اور جزوی مسائل ہمارے ہاں بنیادی اور کلیدی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور جو امور فکر و اعتقاد کی دنیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی ہماری نظر میں کوئی وقعت ہی باقی نہیں رہی۔ ہماری پسند و ناپسند اور وابستگی و لاتعلقی کا معیار جزوی مسائل اور گروہی تعصبات ہیں۔ ایک مثال بظاہر معمولی سی ہے لیکن اس سے ہماری فکری ترجیحات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست نے جنہوں نے ہمارے دینی ماحول میں تربیت حاصل کی ہے گزشتہ دنوں ایک بڑے سیاسی لیڈر کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا کہ وہ بہت اچھا اور صحیح العقیدہ لیڈر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں برسیوں اور عرسوں میں شریک ہونے کا قائل نہیں ہوں۔ ان سے عرض کیا گیا کہ وہ سیاسی لیڈر تو سیکولر نظریات کا قائل ہے اور اجتماعی زندگی میں نفاذ اسلام کو ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں ہمارے دوست کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو سیاسی باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ عرسوں اور برسیوں کا مخالف ہے اس لیے وہ ہمارے مسلک کا ہے اور صحیح العقیدہ ہے۔ یعنی اسلام کے اجتماعی زندگی میں نفاذ کا مسئلہ ’’سیاسی‘‘ ہے اور عرسوں میں شریک ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ اعتقادی ہے۔ آخر یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ ہمارے دینی مدارس کی غلط فکری ترجیحات کا ثمرہ نہیں ہے؟
اب آئیے دوسرے نکتہ کی طرف کہ نفاذ اسلام کے علمی و فکری تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہمارے دینی مدارس کا کردار کیا ہے؟ جہاں تک نفاذ اسلام کی اہمیت کا تعلق ہے کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا اور علمائے اہلِ سنت نے اسے اہم ترین فرائض میں شمار کیا ہے۔ بلکہ ابن حجر مکیؒ اور دیگر ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے خلافت کا قیام ’’اہم الواجبات‘‘ ہے جسے حضرات صحابہ کرامؓ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر ترجیح دی اور آنحضرتؐ کے جنازہ اور تدفین سے قبل حضرت ابوبکرؓ کا بطور خلیفہ انتخاب کیا۔ پھر برصغیر میں ہمارے اکابر کی جنگِ آزادی کا بنیادی مقصد بھی حصولِ آزادی کے بعد نظامِ اسلام کا غلبہ و نفاذ رہا ہے اور پاکستان کا قیام بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرہ پر شریعتِ اسلامیہ کی بالادستی کے لیے عمل میں آیا۔ لیکن اسلام کو ایک اجتماعی نظام کے طور پر ہمارے دینی مدارس میں نہ پڑھایا جا رہا ہے اور نہ طلبہ کی اس انداز میں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ ایک نظام کے طور پر کریں۔ حالانکہ حدیث اور فقہ کی بیشتر کتابیں محدثین اور فقہاء نے اس انداز سے لکھی ہیں کہ ان میں اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کا الگ عنوان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق کے علاوہ تجارت، خلافت، جہاد، دوسری اقوام سے تعلقات، صنعت، زمینداری، حدود و تعزیرات، نظامِ عمل، نظامِ عدالت، معاشرت اور دیگر اجتماعی شعبوں کے بارے میں حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مفصل اور جامع ابواب موجود ہیں جن کے تحت محدثین اور فقہاء نے احکام و ہدایات کا بیش بہا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ لیکن ان ابواب کی تعلیم میں ہمارے اساتذہ کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ہمارے اساتذہ کے علم اور بیان کا سارا زور کتاب الطہارت اور صلوٰۃ کے جزوی مباحث میں صرف ہو جاتا ہے، جبکہ خلافت و امارت، تجارت و صنعت، جہاد، حدود و تعزیرات اور اجتماعی زندگی سے متعلق دیگر مباحث سے یوں کان لپیٹ کر گزر جاتے ہیں جیسے ان ابواب کا ہماری زندگی سے کوئی واسطہ نہ ہو یا جیسے ان ابواب کی احادیث اور فقہی جزئیات منسوخ ہو چکی ہوں اور اب صرف تبرک کے طور پر انہیں دیکھ لینا کافی ہو۔
حالانکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ اجتماعی زندگی سے متعلق ابواب کو زیادہ اہتمام سے پڑھایا جاتا۔ قانون، سیاست، خارجہ پالیسی، جنگ اور معاشرت کے مروجہ افکار و نظریات سے اسلامی تعلیمات کا تقابل کر کے اسلامی احکام کی برتری طلبہ کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی اور انہیں اسلامی افکار و نظریات کے دفاع اور اس کی عملی ترویج کے لیے تیار کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس اہم ترین دینی و قومی ضرورت سے مسلسل صرف نظر کیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی پچانوے فیصد اکثریت خود اسلامی نظام سے ناواقف اور جدید افکار و نظریات کو سمجھنے اور اسلامی احکام کے ساتھ ان کا تقابل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کے اعتراف میں کسی حجاب سے کام نہیں لینا چاہیے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تلافی صورت نکالنی چاہیے۔
آج نفاذ اسلام کی راہ میں ایک بڑی عملی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے رجال کار کا فقدان ہے۔ اسلامی نظام کو سمجھنے والے اور اسے چلانے کی صلاحیت سے بہرہ ور افراد کا تناسب ضرورت سے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ خلا آخر کس نے پر کرنا ہے؟ جس نظامِ تعلیم کو ہم لارڈ میکالے کا نظامِ تعلیم کہتے ہیں اس سے تو یہ توقع ہی عبث ہے کہ وہ اسلامی نظام کے لیے کل پرزے فراہم کرے گا۔ اور اگر دینی نظامِ تعلیم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا نہیں کر رہا تو اسلامی نظام کے لیے رجالِ کار کیا آسمان سے اتریں گے؟
دینی مدارس کے اجتماعی کردار کے منفی پہلوؤں کے بارے میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش موجود ہے بلکہ بہت کچھ کہنے کی ضرورت ہے لیکن ہم صرف مذکورہ دو اصولی مباحث کے حوالے سے توجہ دلاتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے علمائے کرام، دینی مدارس کی اجتماعی قیادت بالخصوص وفاق المدارس العربیہ، تنظیم المدارس اور وفاق المدارس السلفیہ کے ارباب حل و عقد سے گزارش کریں گے کہ وہ اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور یورپ کے لادینی فلسفۂ حیات کو فکری محاذ پر شکست دینے اور نفاذِ اسلام کے لیے رجال کار کی فراہمی کے حوالہ سے اپنے کردار کا ازسرنو تعین کریں۔ ورنہ وہ اپنی موجودہ کارکردگی اور کردار کے حوالہ سے نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں گے اور نہ ہی مؤرخ کا قلم ہی ان کے اس منفی کردار کو بے نقاب کرنے میں کسی رعایت اور نرمی سے کام لے گا۔
موجودہ طریقۂ انتخابات شرعی لحاظ سے اصلاح طلب ہے
وفاقی شرعی عدالت کا ایک اہم فیصلہ
ادارہ
وفاقی شرعی عدالت میں اوریجنل جیورسڈکشن۔
حاضر
عزت مآب جناب جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس۔ عزت مآب جناب جسٹس ڈاکٹر مفتی شجاعت علی قادری۔ عزت مآب جناب جسٹس مفتخر الدین۔ عزت مآب جناب جسٹس عبادت یار خان۔ عزت مآب جناب جسٹس علامہ ڈاکٹر فدا محمد خان۔
شریعت درخواست نمبر ۱۳ ایل آف ۱۹۸۸ء
محمد صلاح الدین بنام حکومتِ پاکستان
شریعت درخواست نمبر ۱۸ آئی آف ۱۹۸۸ء
ملک محمد عثمان بنام حکومتِ پاکستان اور دیگر
شریعت درخواست نمبر ۲۶ آئی آف ۱۹۸۸ء
بیگم یاسمین رضا بنام حکومتِ پاکستان
شریعت درخواست نمبر ۴ کے آف ۱۹۸۸ء
عبد الرب جعفری بنام حکومتِ پاکستان
شریعت درخواست نمبر ۳ ایل آف ۱۹۸۹ء
بشیر احمد نوید بنام حکومتِ پاکستان
وکیل برائے درخواست گزار بسلسلہ شریعت درخواست نمبر ۱۳ ایل آف ۱۹۸۸ء
جناب خالد ایم اسحاق ایڈووکیٹ۔ مسٹر جاوید حسن ایڈووکیٹ
درخواست گزار بسلسلہ ایس پی نمبر ۱۹ آئی آف ۱۹۸۸ء
جناب حبیب الوہاب خیری ایڈووکیٹ
وکیل برائے درخواست بسلسلہ ایس پی نمبر ۳ ایل آف ۱۹۸۸ء
جناب محمد اعظم سلطان پوری ایڈووکیٹ
درخواست گزار
جناب صلاح الدین۔ جناب مجیب الرحمٰن شامی۔ جناب الطاف حسین قریشی۔ ملک محمد عثمان۔ بیگم یاسمین رضا۔ جناب بشیر احمد نوید۔ جناب عبد الرب جعفری۔
برائے وفاقی حکومت
حافظ ایس اے رحمٰن (اسٹینڈنگ کونسل برائے وفاقی حکومت)۔ جناب غلام مصطفٰی اعوان (اسٹینڈنگ کونسل برائے وفاقی حکومت)۔ جناب محمد اسلم جنجوعہ (اسسٹنٹ سیکرٹری شعبہ پارلیمانی امور، اسلام آباد)۔ جناب محمد اکرم (اسسٹنٹ سیکرٹری شعبہ پارلیمانی امور)۔ جناب طارق ایوب خان (سیکشن آفیسر وزارتِ داخلہ، اسلام آباد)
برائے حکومتِ پنجاب
سید افتخار حسین (اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل)۔ جناب نذیر احمد غازی (اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل)۔
برائے حکومتِ بلوچستان
جناب ایم یعقوب یوسف زئی (اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل)۔ جناب ایم شریف رکھسانی (اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل)۔ جناب محمد افضل (ڈپٹی سیکرٹری جنرل بلوچستان اسمبلی)
برائے حکومتِ سندھ
جناب کے ایم ندیم (اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل)۔ جناب عبد الوحید صدیقی (ایڈووکیٹ)
مشیرانِ عدالت اور علماء
مولانا گوہر رحمٰن۔ مولانا محمد طاسین۔ جناب ریاض الحسن نوری۔ مولانا صلاح الدین یوسف۔ ڈاکٹر محمد امین۔ ڈاکٹر احسن الحق۔ مولانا عبد الشہید۔ ڈاکٹر اختر سعید۔ ڈاکٹر نثار احمد۔ علامہ جاوید الغامدی۔
دیگر
جناب رفیق احمد باجوہ ایڈووکیٹ۔ جناب جی ایم سلیم ایڈووکیٹ۔ سید احمد حسنین ایڈووکیٹ۔ جناب رشید مرتضٰی قریشی ایڈووکیٹ۔ حاجی محمد معز الدین حبیب اللہ۔ جناب عبد الرشید۔ سید فدائے مہدی شاہ۔ شیخ مشتاق علی ایڈووکیٹ۔ جناب ایم اے شیخ ایڈووکیٹ۔ جناب ایم اے رشید صحافی۔ مولانا وصی مظہر ندوی۔ ڈاکٹر محمد یونس۔ صوفی محمد صدیق۔ ملک ظہور احمد۔ چوہدری محمد اقبال ایڈووکیٹ۔
تواریخ سماعت
لاہور میں ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۲۹ اور ۳۰ مئی ۱۹۸۹ء۔ کراچی میں ۲۶، ۲۷ اور ۲۸ فروری ۱۹۸۹ء
فیصلہ
(۱) مندرجہ بالا شریعت درخواستیں، دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل ۲۰۳ ڈی کے تحت اس سوال پر فیصلہ کے لیے داخل کی گئی ہیں کہ پاکستان کا پورا نظامِ انتخابات غیر اسلامی، خلافِ شریعت اور معاشرے کے اس تصور کے برعکس ہے جو قرآن و سنت میں نظر آتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی تشکیل، انتخابی مہم، لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کنوینگ کا طریقہ، بالغ رائے دہی اور اس تمام عمل کے ذریعے بننے والے قانون ساز ادارے سب کے سب مکمل طور پر غیر اسلامی ہیں۔ لہٰذا اس پورے نظام کو کلیتاً ختم کر کے ’’قرارداد مقاصد‘‘ کے مطابق ایک نئے نظام سے تبدیل کیا جانا چاہیئے کیونکہ یہی ریاست کا وہ بنیادی پتھر ہے جو بانیانِ پاکستان کے ہاتھوں رکھا گیا تھا۔
یہ درخواستیں نومبر ۱۹۸۸ء کے عام انتخابات کے بعد جلد ہی داخل کر دی گئی تھیں۔ درخواست گزاروں کے مطابق انہوں نے ان خامیوں کے ازالے کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کر کے سڑکوں پر دھول اڑانے اور ملک کی سالمیت کے لیے خطرات پیدا کرنے کے بجائے اس عدالت سے رکوع کرنے کا پُراَمن طریقہ اختیار کیا ہے۔
(۲) عدالت کی جانب سے ان درخواستوں کے حوالے سے اطلاع نامے جاری کر کے عوام کو دعوت دی گئی ہے کہ ان میں سے جو بھی چاہے اس بحث میں حصہ لے اور ان سوالات پر قابل اجازت حدود کے اندر اپنے نظریات کا اظہار کرے جو ان درخواستوں میں شامل ہیں۔ یہ عام نوٹس نہ صرف ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوئے بلکہ انفرادی طور پر ملک میں عدلیہ کے مشیروں اور اسلامی اسکالروں کو بھی بھیجے گئے۔ ان نوٹسوں کی تعمیل جوابدہ حکومتوں پر بھی کی گئی۔
(۳) ان کے جواب میں متعدد فضلاء ہمارے سامنے پیش ہوئے، ان میں صرف علماء اور مذہبی اسکالر ہی نہیں بلکہ ملک کے ایسے ممتاز وکلاء بھی شامل تھے جنہیں قانون کے پیشے میں اعتبار و احترام کا مقام حاصل ہے۔ ان کی آراء سے استفادے اور اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں عدالت کے مشیروں کو سننے کے بعد، اب ہمیں آئین میں بیان کردہ اپنے حدود کار کے مطابق ان درخواستوں کا فیصلہ کرنا ہے۔
دورانِ سماعت ہم نے اس بات کو پیشِ نظر رکھا ہے، اس بارے میں محتاط رہے ہیں اور اب پھر اسے دہراتے ہیں کہ کسی قانون یا ایسی رسم یا رواج کو، جو قانون کی طاقت رکھتا ہو، قرآن و اور سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کے معاملے میں وفاقی شرعی عدالت کا دائرہ اختیار، آئین کے آرٹیکل ۲۰۳ بی شق سی کے ذریعے محدود کر دیا گیا ہے جس کی بنا پر ’’آئین‘‘ مسلم شخصی قوانین، ایک مالیاتی قانون اور کسی بھی عدالت کے طریقہ کار کا قانون ہماری چھان بین کے حدود سے خارج ہیں۔ ہمارے مقصد کے لیے قانون کی تعریف یوں کی گئی ہے:
’’(سی) ’’قانون‘‘ میں ہر ایسی رسم یا رواج شامل ہے جو قانون کا اثر رکھتا ہو مگر اس میں دستور شامل نہیں ہے۔‘‘
(۴) اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ایسے معاملات میں جو آئین میں خاص طور پر نظامِ قانون کے طریقہ کار کے ڈھانچے اور موضوعات سے متعلق ہوں وہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہیں اور ایسے معاملات میں ہم کوئی داد رسی کرنے سے قاصر ہیں۔
(۵) یہ استدلال کیا گیا تھا کہ ’’قرارداد مقاصد‘‘ آئین سے بالاتر ہے اور آئین کے اندر اس کی شمولیت، اوپر سے درج کی جانے والی تعریفی شق میں، اختیار کے استعمال پر عائد کی جانے والی پابندی کو تحلیل کرتی اور آئین سے متعلق امور کو بھی ہمارے سامنے قابلِ فیصلہ بناتی ہے۔ تاہم کیا یہ قرارداد، جو اَب دستور کا ایک حصہ بن چکی ہے، آرٹیکل ۲۰۳ کی شق سی میں عائد کی جانے والی پابندی کو واقعی ختم کرتی ہے؟ یہ بات ابھی غیر یقینی ہے۔ اور یہ بات بھی کیا یہ قرارداد، جو دستور کے تعارفی باب میں شامل ہے، عدالت کے ذریعے کلی طور پر قابلِ نفاذ ہے، بحث طلب ہے۔ مزید یہ کہ یہ دلیل صرف رفیق احمد باجوہ ایڈووکیٹ نے اپنے دلائل کے دوران اتفاقی طور پر پیش کی تھی۔ چونکہ اس سوال پر کوئی عام نوٹس جاری نہیں کیا گیا اور اس کو گہرائی کے ساتھ پرکھا نہیں جا سکا، اس لیے اس معاملے کو ہم کھلا چھوڑتے ہیں۔
(۶) آخر میں ہمارے لیے صرف وہ قوانین یا ان کے متعلقات رہ جاتے ہیں جو آئین کا حصہ نہیں بلکہ عام قوانین کے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنہیں آئین میں بیان کردہ مقاصد کے حصول کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ قوانین قرآن و سنت کے خلاف پائے جائیں تو ہم انہیں ختم کرنے اور آئینی پابندیوں کے خلاف ورزی کیے بغیر ان میں ایسی اصلاحات تجویز کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جن کے ذریعے انہیں شریعت کے تصور کے مطابق ڈھالا جا سکے۔
(۷) ان درخواستوں میں ہمارے مقصد سے متعلق قوانین مندرجہ ذیل ہیں:
- عوامی نمائندگی کا قانون مجریہ ۱۹۷۶ء
- ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا (انتخابی) حکم مجریہ ۱۹۷۷ء
(۸) یہ فیصلہ بہرکیف ’’عوامی نمائندگی کے قانون‘‘ ، ‘‘ ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے (انتخابی) حکم‘‘ اور ان کے مختلف حصوں سے بحث کرے گا، جنہیں درخواست گزاروں نے مذکورہ بالا درخواستوں میں چیلنج کیا ہے۔ یہ دونوں قوانین ایک ہی موضوع سے بحث کرتے ہیں اس لیے انہیں ساتھ ساتھ نمٹایا جا سکتا ہے۔
(۹) اب مناسب ہو گا کہ ان طویل مباحث اور دلائل کا خلاصہ یہاں درج کر دیا جائے جو سماعت کے دوران ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔
(۱۰) یہ استدلال کیا گیا کہ پوری انتخابی مہم ایک سرکس یا میلے کے انداز میں چلائی جاتی ہے۔ ہر امیدوار کی پہلی ترجیح اپنی ذاتی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اپنے حریف امیدوار کی کردارکشی ہوتی ہے۔ منافقت اور فریب کا لبادہ اوڑھے ہوئے امیدوار ڈینگیں ہانک کر، شیخیاں بگھار کر، لالچ، دھونس، دھمکی اور جھوٹے وعدوں کے ہتھکنڈے استعمال کر کے، اپنی جھولی میں حتی الامکان زیادہ سے زیادہ ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے، ایک ایک دروازے پر پہنچ کر ووٹروں کا تعاقب کرتا ہے۔ وہ تنخواہ یافتہ کارکنوں کی فوج حتٰی کہ بعض اوقات انتخابی مہم کے حربوں میں خصوصی طور پر تربیت یافتہ بیرونی ماہر بھی رکھتا ہے۔ امیدواروں کی بینروں، پوسٹروں اور پلے کارڈوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر تشہیر کی جاتی ہے۔ مرسیڈیز، پجیرو اور ٹرکوں پر سوار کرائے پر حاصل کیے جانے والے ’’رضاکاروں‘‘ کے جلوس، سڑکوں پر محلے محلے اور گاؤں گاؤں نعرے لگاتے ہوئے گشت کرتے ہیں تاکہ اپنے امیدواروں کے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ امیدوار کی خواہش کے مطابق اس کے اپنے خرچ پر ہوتا ہے۔ حمایت حاصل کرنے کے لیے علاقائی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور ایسے ہی دوسرے تعصبات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ووٹ خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقوم بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بوگس ووٹنگ اور ایک ووٹر کی جگہ کسی دوسرے کا جعلی طور پر ووٹ ڈالنا، انتخابات میں ایک معمول کی بات ہے۔ بالآخر جو سب سے اونچے داؤ لگا کر یہ کھیل کھیلتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔
شریعت کی رو سے بھلا کس طرح ان چیزوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور ایسے آسمان سے سیراب ہونے کے نتیجے میں رونما ہونے والی پیداوار کو آخر کس طرح ’’امیر‘‘ یعنی امتِ مسلمہ کے اعتماد کے اہل اور امین کا مقام دیا جا سکتا ہے؟ (جبکہ قرآن و سنت کے احکام یہ ہیں کہ):
’’اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اِترانے والے خودپسند کو پسند نہیں کرتا۔‘‘ (لقمان ۱۸)
’’اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) تکبر کرنے اور بڑائی جتانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔‘‘ (النساء ۳۶)
’’اے ایمان والو! خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔‘‘ (المائدہ ۸)
’’حضرت ابوموسٰیؓ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میرے ساتھ میرے دو چچا زاد بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بولا یا رسول اللہ! جو ملک اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان میں سے کسی ملک کی حکومت ہمیں دے دیجئے، اور دوسرے نے بھی یہی کہا۔ آپؐ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم کسی کو اس امر کا حاکم نہیں بناتے جو اس حکومت کی درخواست کرے اور نہ اس کو جو اس کی حرص کرے۔‘‘ (حوالہ صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۳)
’’آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں زیادہ جھوٹا ہمارے نزدیک وہی ہے جو حکومت طلب کرے۔‘‘ (ابوداؤد ج ۲ ص ۴۵۸)
’’ہم اس کو عامل مقرر نہیں کرتے جو اس کا ارادہ کرے۔‘‘ (کنزل العمال ج ۶ ص ۴۷۔ حدیث نمبر ۱۴۷۵۸ طبع بیروت)
(۱۱) دورانِ بحث کہا گیا کہ یہ قانون عہدے اور منصب کو شکار کرنے اور اسے جائز اور ناجائز ذرائع سے حاصل کرنے کے رجحان کو دبانے کے بجائے اس رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جلتی پر تیل چھڑکنے کے لیے انتخابات پر بھاری رقوم کے خرچ کو ’’انتخابی مصارف‘‘ کا نام دے کر قانونی طور پر جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ نتیجتاً تجوری اور تشہیر، چور بازاری، منشیات اور بلیک میلنگ کا کاروبار کرنے والوں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے طاقتور ترین ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ امانت دار، راست باز اور خدا ترس لوگ ایسے کھیل میں قسمت آزمائی کے لیے شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ پورے کا پورا میکانزم اور نظام کلی طور پر اسلام کے احکام کے خلاف ہے۔
(۱۲) ایک سابقہ مقدمے کا حوالہ بھی دیا گیا جس میں مرحوم جسٹس بی زیڈ کیکاؤس اور دیگر افراد نے اس وقت کی وفاقی شرعی عدالت کے سامنے ایسے ہی اعتراضات اٹھائے تھے اور عدالت کے اس وقت کے سربراہ نے اپنے فیصلے میں اس سلسلے میں بعض سفارشات پیش کی تھیں۔ یہ فیصلہ پی ایل ڈی ۱۹۸۱ء ایف سی ایس (مسٹر بی زیڈ کیکاؤس بنام وفاقی حکومت پاکستان) میں درج ہے۔
(۱۳) یہاں وفاقی شرعی عدالت کے اس وقت کے سربراہ جناب جسٹس صلاح الدین احمد کے فیصلے کا ایک اقتباس پیش کرنا مفید ہو گا۔ فاضل جج نے عوامی نمائندگی کے قانون نمبر ۸۵ کے حوالے سے یہ تبصرہ کیا:
’’اس سوال کا ایک اور پہلو بھی ہے جو غور و خوض کا متقاضی ہے۔ پارلیمنٹ کو آئین کے آرٹیکل ۶۲ ڈی، ۶۳ (۱) (ای) اور ۱۱۳ کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان فرائض اور ذمہ داریوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیئے جو آئین اور اسلامی احکام کی رو سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ آئین میں دیے گئے یہ امور پارلیمنٹ کو مقننہ کے ارکان کی اہلیت اور نا اہلی کی شرائط میں اضافے کے لیے ایک صوابدیدی اختیار فراہم کرتے ہیں جبکہ ’’ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا (انتخابی) حکم مجریہ ۱۹۷۳ء‘‘ اور ’’عوامی نمائندگی کا قانون مجریہ ۱۹۷۶ء‘‘ وضع کرتے وقت پارلیمان آئین اور اسلامی احکام کے تحت عائد ہونے والے ان فرائض اور ذمہ داریوں کو یاد رکھنے میں ناکام رہی ہے، جیسا کہ ابھی واضح ہو گا۔
قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام قانون سازی ہے۔ آئین، پالیسی سازی کے اصول فراہم کرتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل ۲۹ کی رو سے ریاست کے ہر عضو اور ادارے اور ہر شخص کی، جو ریاست کے کسی عضو یا ادارے کی جانب سے فرائض انجام دے رہا ہو، یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک یہ اصول اس کے ادارے کے وظائف سے متعلق ہیں، وہ ان کے مطابق عمل کرے۔ آرٹیکل ۳۰ کے تحت یہ فیصلہ کرنا کسی بھی عضو ریاست یا اس کی جانب سے فرائض انجام دینے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی کیا جانے والا کوئی بھی اقدام آیا پالیسی کے اصولوں کے مطابق ہے؟ آرٹیکل ۳۱ کی رو سے مسلمانانِ پاکستان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ اور انہیں ایسی سہولتیں فراہم کی جانی چاہئیں جن کے ذریعے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔‘‘
(۱۴) اس فیصلے کے بعد دستوری ترمیم کی گئی اور آئین کے آرٹیکل ۶۲، ۶۳ اور ۱۱۳، ۱۹۸۵ء کے صدارتی حکم نمبر ۱۴ سے بدل دیے گئے اور اسے ۲ مارچ ۱۹۸۵ء سے مؤثر قرار دیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی قانون ساز اداروں کے ارکان کی اہلیت اور نا اہلی کی شرائط کا تعین ازسرنو کیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ اب ان امیدواروں کی شرائطِ اہلیت کے بارے میں واضح طور پر بتاتے ہیں جنہیں ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ (ملاحظہ کیجئے آرٹیکل ۱۱۳ دستورِ اسلامی جمہوریہ پاکستان)
(۱۵) اس مرحلہ پر ان آرٹیکلز کو یہاں بالتفصیل نقل کر دینا مناسب ہو گا:
۶۲۔ کوئی شخص مجلس شورٰی (پارلیمنٹ) کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہو گا اگر
(الف) وہ پاکستان کا شہری نہ ہو۔
(ب) وہ قومی اسمبلی کی صورت میں پچیس سال سے کم عمر کا ہو اور اس اسمبلی میں کسی مسلم یا غیر مسلم نشست کے لیے، جیسی بھی صورت ہو، انتخاب کے لیے انتخابی فہرست میں ووٹر کی حیثیت سے درج نہ ہو۔
(ج) وہ سینٹ کی صورت میں تیس سال سے کمر عمر کا ہو اور کسی صوبے میں کسی علاقے میں یا جیسی بھی صورت ہو وفاقی دارالحکومت یا وفاق کے زیرانتظام قبائلی علاقہ جات میں جہاں سے وہ رکنیت چاہتا ہو بطور ووٹر درج نہ ہو۔
(د) وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکامِ اسلام سے انحراف میں مشہور ہو۔
(ہ) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو۔
(د) وہ سمجھدار، پارسا نہ ہو اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو۔
(ز) کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ ہو۔
(ح) اس نے قیامِ پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریۂ پاکستان کی مخالفت کی ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ پیرا
(د) اور (ہ) میں مصرحہ نا اہلیتوں کا کسی ایسے شخص پر اطلاق نہیں ہو گا جو غیر مسلم ہو، لیکن ایسا شخص اچھی شہرت کا حامل ہو گا اور
(ط) وہ ایسی دیگر اہلیتوں کا حامل نہ ہو جو مجلس شورٰی (پارلیمنٹ) کے ایکٹ کے ذریعے مقرر کی گئی ہوں۰
۶۳۔ (۱) کوئی شخص مجلس شورٰی (پارلیمنٹ) کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے اور رکن رہنے کے لیے نا اہل ہو گا اگر
(الف) وہ فاتر العقل ہو اور کسی مجاز عدالت کی طرف سے ایسا قرار دیا گیا ہو، یا
(ب) وہ غیر برات یافتہ دیوالیہ ہو، یا
(ج) وہ پاکستان کا شہری نہ رہے اور کسی بیرونی ریاست کی شہریت حاصل کرے، یا
(د) وہ پاکستان کی ملازمت میں کسی منفعت بخش عہدے پر فائز ہو ما سوائے ایسے عہدے کے جسے قانون کے ذریعے ایسا عہدہ قرار دیا گیا ہو جس پر فائز شخص نا اہل نہیں ہوتا، یا
(ہ) اگر وہ کسی ایسی آئینی ہیئت کی ملازمت میں ہو جو حکومت کی ملکیت یا اس کے زیرنگرانی ہو یا جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مفاد رکھتی ہو، یا
(و) شہریت پاکستان ایکٹ ۱۹۵۱ء (نمبر ۲ بابت ۱۹۵۱ء) کی دفعہ ۱۴ ب کی وجہ سے پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اسے فی الوقت آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا نااہل قرار دے دیا گیا ہو، یا
(ز) وہ کسی ایسی رائے کی تشہیر کر رہا ہو یا کسی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے اقتدارِ اعلٰی، سالمیت یا سلامتی یا اخلاقیات، یا امن عامہ کے قیام یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانت داری یا آزادی کے لیے مضر ہو۔ یا جو پاکستان کی مسلح افواج یا عدلیہ کو بدنام کرے یا اس کی تضحیک کا باعث ہو، یا
(ح) اسے کسی ایسے جرم کے لیے سزا یابی پر جس میں چیف الیکشن کمشنر کی رائے میں اخلاقی پستی ملوث ہو، کم از کم دو سال کے لیے قید کی سزا دی گئی ہو، تاوقتیکہ اس کی رہائی کو پانچ سال کی مدت نہ گزر چکی ہو، یا
(ط) اسے پاکستان کی ملازمت سے غلط روی کی بنا پر برطرف کر دیا گیا ہو، تاوقتیکہ اس کی برطرفی کو پانچ سال کی مدت نہ گزر گئی ہو، یا
(ی) اسے پاکستان کی ملازمت سے غلط روی کی بنا پر ہٹا دیا گیا ہو یا جبری طور پر فارغ خدمت ہونے کو تین سال کی مدت نہ گزر گئی ہو، یا
(ک) وہ پاکستان کی کسی آئینی ہیئت یا کسی ایسی ہیئت کو جو حکومت کی ملکیت یا اس کے زیرنگرانی ہو یا جس میں حکومت تعدیلی حصہ یا مفاد رکھتی ہو، ملازمت میں رہ چکا ہو، تاوقتیکہ اس کی مذکورہ ملازمت ختم ہوئے دو سال کی مدت نہ گزر گئی ہو، یا
(ل) اسے فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون کے تحت کسی بدعنوانی یا غیر قانونی حرکت کا مجرم قرار دیا جائے، تاوقتیکہ اس تاریخ کو جس پر مذکورہ حکم مؤثر ہوا ہو پانچ سال کا عرصہ نہ گزر گیا ہو، یا
(م) وہ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ ۱۹۶۲ء (نمبر ۳ بابت ۱۹۶۲ء) کی دفعہ ۷ کے تحت سزا یاب ہو چکا ہو، تاوقتیکہ مذکورہ سزا یابی کو پانچ سال کی مدت نہ گزر گئی ہو، یا
(ن) وہ، خواہ بذاتِ خود یا اس کے مفاد میں یا اس کے فائدے کے لیے یا اس کے حساب میں یا کسی ہندو غیر منقسم خاندان کے رکن کے طور پر کسی شخص یا اشخاص کی جماعت کے ذریعے کسی معاہدے میں کوئی حصہ یا مفاد رکھتا ہو، جو انجمن امداد باہمی اور حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، جو حکومت کو مال فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیے ہوئے کسی معاہدے کی تکمیل یا خدمات کی انجام دہی کے لیے ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرے کے تحت نا اہلیت کا اطلاق کسی شخص پر نہیں ہو گا
(اول) جبکہ معاہدے میں حصہ یا مفاد اس کو وراثت یا جانشینی کے ذریعے یا موصی لہ وصی یا مہتمم ترکہ کے طور پر منتقل ہوا ہو، جب تک اس کو اس کے اس طور منتقل ہونے کے بعد چھ ماہ کا عرصہ نہ گزر جائے۔
(دوم) جبکہ معاہدہ کمپنیات آرڈیننس ۱۹۸۴ء (نمبر ۴۷ مجریہ ۱۹۸۴ء) میں تعریف کردہ کسی ایسی کمپنی عامہ نے کیا ہو یا اس کی طرف سے کیا گیا ہو جس کا وہ حصہ دار ہو، لیکن کمپنی کے تحت کسی منفعت بخش عہدے پر فائز مختار انتظامی نہ ہو، یا
(سوم) جبکہ وہ ایک غیر منقسم ہندو خاندان کا فرد ہو اور اس معاہدے میں، جو خاندان کے کسی فرد نے علیحدہ کاروبار کے دوران کیا ہو، کوئی حصہ یا مفاد نہ رکھتا ہو۔ (تشریح) اس آرٹیکل میں ’’مال‘‘ میں زرعی پیداوار یا جنس جو اس نے کاشت یا پیدا کی ہو یا ایسا مال شامل نہیں ہے جسے فراہم کرنا اس پر حکومت کی ہدایت یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت فرض یا وہ اس کے لیے پابند ہو۔
(س) وہ پاکستان کی ملازمت میں حسب ذیل عہدوں کے علاوہ کسی منفعت بخش عہدے پر فائز ہو، یعنی
(اول) کسی عہدہ جو ایسا کل وقتی عہدہ نہ ہو جس کا معاوضہ یا و تنخواہ کے ذریعے یا فیس کے ذریعے ملتا ہو
(دوم) نمبردار کا عہدہ خواہ اس نام سے یا کسی دوسرے نام سے موسوم ہو
(چہارم) کوہ عہدہ جس پر فائز شخص مذکورہ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے کسی فوج کی تشکیل یا قیام کا حکم وضع کرنے والے کسی قانون کے تحت فوجی تربیت یا فوجی ملازمت کے لیے طلب کیے جانے کا مستوجب ہو۔ یا
(ع) اسے فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے تحت مجلس شورٰی (پارلیمنٹ) یا کسی صوبائی اسمبلی کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہو۔
۶۳۔ (۲) اگر کوئی سوال اٹھے کہ آیا مجلس شورٰی (پارلیمنٹ) کا کوئی رکن، رکن رہنے کے لیے نااہل ہو گیا ہے تو سپیکر یا، جیسی بھی صورت ہو، چیئرمین اس سوال کو فیصلہ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا اور چیف الیکشن کمشنر کی یہ رائے ہو کہ رکن نا اہل ہو گیا ہے تو وہ رکن نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔
۱۱۳۔ آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ میں مندرج قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے اہلیت اور نا اہلیت کا کسی صوبائی اسمبلی کے لیے بھی اسی طرح اطلاق ہو گا گویا کہ اس میں ’’قومی اسمبلی‘‘ کا حوالہ ’’صوبائی اسمبلی‘‘ کا حوالہ ہو۔
(۱۶) رکنیت کی اہلیت اور عدمِ اہلیت کی یہ شرائط ’’ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے (انتخابی) حکم مجریہ ۱۹۷۷ء‘‘ کے آرٹیکل ۱۰ اور ۱۱، ’’۱۹۷۷ء کے صدارتی حکم نمبر ۵‘‘ اور ’’عوامی نمائندگی کے قانون مجریہ ۱۹۷۶ء‘‘ کی دفعہ ۹۹ میں بھی دہرائی گئی ہیں۔
(۱۷) درخواست گزاروں کی طرف سے آئین کے آرٹیکل ۶۳ کے ان ابتدائی الفاظ پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ ’’کوئی شخص مجلس شورٰی (پارلیمنٹ) کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہو گا اگر (الف) ۔۔۔ (ب) ۔۔۔ (ج) ۔۔۔
(د) وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکامِ اسلام سے انحراف میں مشہور ہو۔
(ہ) وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو۔
(د) وہ سمجھدار، پارسا نہ ہو اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو۔
(ز) کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ ہو۔
(ح) اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریۂ پاکستان کی مخالفت کی ہو۔
(۱۸) یہ دلیل دی گئی کہ رکن شورٰی میں یہ صفات لازماً موجود ہونی چاہئیں۔ کسی امیدوار کی طرف سے اپنے آپ کو ان صفات کا (اعلٰی یا ادنیٰ درجہ میں) حامل ثابت کرنے میں ناکامی، پہلے ہی قدم پر اسے انتخابی عمل سے الگ کر دے گی اور یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ کسی انتخابی نشست کے لیے مقابلہ کرنے کا اہل ہے۔
(۱۹) دلائل کا اصل زور اس پر تھا کہ ’’عوامی نمائندگی کا قانون‘‘ اور ’’ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا (انتخابی) حکم‘‘ کسی بھی مرحلے پر کوئی ایسا فورم فراہم کرنے میں ناکام ہیں جس کے ذریعے آئین کے آرٹیکل ۶۲،۶۳ اور ۱۱۳ میں دی گئی ہدایات کے تقاضوں کو مؤثر طور پر پورا کیا جا سکے۔ اس ناکامی نے ان آرٹیکلز کو عملاً بے جان بنا دیا ہے اور ناپسندیدہ افراد کے لیے شورٰی میں پہنچنے کا راستہ مہیا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسے افراد کا اجتماع وجود میں آتا ہے جو سورہ نساء کی آیت ۵۸ کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ’’دارالندوہ‘‘ (مشرکین مکہ کی مجلس مشاورت) جیسی کوئی چیز تو بن سکتی ہے مگر ’’دار ارقم‘‘ (نبی اکرمؐ اور صحابہؓ کی مشاورت گاہ) جیسی شورٰی جس کا تصور اسلام پیش کرتا ہے وجود میں نہیں آ سکتی۔ شریعت کی مطلوبہ صفات سے، جنہیں بڑی حد تک آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ میں یکجا کر دیا گیا ہے، محروم ارکان جو زندگی کے کسی بھی نظریے کے حامل اور کسی بھی دوسرے نظام کی قدروں کے مداح ہو سکتے ہیں، یقیناً شریعت کے مقرر کردہ معیار پر پورے نہیں اتر سکتے۔ اس پورے قانون کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ملے گی جس سے امیدواروں کی چھان پھٹک ممکن ہو سکے۔
(۲۰) دورانِ بحث کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ کو عوامی نمائندگی کے قانون کی دفعہ ۱۴ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تب بھی صورتِ حال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درحقیقت ان دونوں قوانین کا موضوعاتی مواد ہی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا۔
(۲۱) درخواست گزاروں کی طرف اس دعوے کے ثبوت کے طور پر کہ اعتماد صرف ان لوگوں پر ظاہر کیا جانا چاہیئے جو اس پر پورا اترنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اور یہ کہ اقتدار کے بھوکے افراد کو مسترد کر دینا چاہیئے اور صرف ان لوگوں کو چنا جانا چاہیئے جو منصب کے اہل ہوں، مندرجہ ذیل قرآنی آیات اور احادیث نبویؐ پیش کی گئیں:
’’خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔‘‘ (النساء ۵۸)
’’کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، بے علموں کے برابر ہو سکتے ہیں؟‘‘ (الزمر ۹)
’’جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیئے۔‘‘ (سنن ابی داؤد ۔ باب فی المشورہ ج ۲ ص ۳۳۳ ۔ بیروت)
(۲۲) نا اہل لوگوں کو کوئی انتخابی عہدہ سپرد کر دینے کے جو نتائج ہو سکتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں:
’’حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں (ایک دن) نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے اس حالت میں ایک اعرابی آپؐ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپؐ نے فرمایا جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہو گا؟ آپؐ نے فرمایا جب کام نا اہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔‘‘ (بخاری شریف ۔ جلد اول ص ۱۱۰)
(۲۳) عوامی نمائندگی کے قانون کی دفعہ ۱۴ کا حوالہ پیش کرتے ہوئے استدلال کیا گیا کہ یہ قانون اگر کچھ کرتا ہے ہے تو وہ صرف آئین کے آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ امیدوار کی اہلیت کے تعین کے سلسلے میں ریٹرننگ افسر کی مدد کے لیے لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے بجائے اس آرٹیکل کو ’’اسکروٹنی‘‘ کا عنوان دے کر انہیں ’’شہادتِ حق‘‘ کی ذمہ داری کو ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس چھان بین کے دوران ہونے والی کارروائی کی نوعیت قطعی سرسری ہوتی ہے۔ یہ صرف دفعہ ۱۳ کے تحت زر ضمانت کے سوال اور دفعہ ۱۳ میں دی گئی چند دوسری غیر اہم دفعات تک محدود ہے۔ دفعہ ۱۴ ذیل میں نقل کی جا رہی ہے:
’’۱۴۔ اسکروٹنی ۔۔۔۔
(۱) امیدوار، اس کے الیکشن ایجنٹس، مجوزین اور مویدین اور امیدواروں کی طرف سے اس سلسلے میں اجازت یافتہ ایک اور شخص سمیت یہ تمام لوگ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران حاضر رہ سکتے ہیں اور ریٹرننگ افسر انہیں ان تمام کاغذات نامزدگی کی چھان بین کے لیے مناسب موقع دے سکتا ہے جو دفعہ ۱۳ کے تحت اس کے سپرد کیے گئے ہوں۔
(۲) ان افراد کی موجودگی میں جنہیں ذیلی دفعہ (۱) کے تحت چھان بین کے دوران حاضر رہنے کی اجازت ہے، ریٹرننگ افسر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور کسی نامزدگی پر ایسے کسی شخص کی طرف سے ہونے والے اعتراض کا فیصلہ کرے گا۔
(۳) ریٹرننگ افسر خود اپنی تحریک یا کسی کی نشاندہی پر اس سرسری تفتیش کو جس طرح مناسب سمجھے گا انجام دے سکے گا اور کاغذات نامزدگی کو مسترد کر سکے گا اگر وہ مطمئن ہو کہ
(الف) امیدوار بحیثیت رکن منتخب ہونے کا اہل نہیں ہے۔
(ب) مجوز یا موید کاغذ نامزدگی پر دستخط کرنے کی مطلوبہ شرائط پوری نہیں کرتے (اضافہ بذریعہ حکم ۱۴ مجریہ ۱۹۸۸ء)۔
(ج) دفعہ ۱۲ یا دفعہ ۱۳ کی کوئی شرط پوری نہیں کی گئی ہے، یا
(د) مجوز یا موید کے دستخط اصلی نہیں ہیں (اضافہ بذریعہ حکم ۱۴ مجریہ ۱۹۸۸ء)
۔۔۔ تاہم ۔۔۔
(۱) ایک کاغذ نامزدگی مسترد کر دیے جانے سے کسی امیدوار کی دوسرے کاغذ نامزدگی کی رو سے جائز قرار پانے والی نامزدگی مسترد نہیں ہو گی۔
(۲) ریٹرننگ افسر کسی کاغذ نامزدگی کو کسی ایسے نقص کے سبب جو بنیادی نوعیت کا نہ ہو، مسترد نہیں کرے گا۔ نام، انتخابی فہرست کے نمبر شمار اور امیدوار (یا مجوز یا موید) کے دوسرے کوائف سمیت ایسے نقائص میں چھوٹ دے سکے گا جو بعد میں درست کیے جا سکتے ہوں (حکم ۱۴، ۱۹۸۸ء)۔
(۳) ریٹرننگ افسر انتخابی فہرست کے مندرجات کے درست اور جائز ہونے کی تحقیق کرے گا لیکن کاغذ نامزدگی کو، انتخابی فہرست میں درج کسی ایسی بات کی بنیاد پر جس میں واضح غلطی یا نقص ہو، مسترد نہیں کرے گا۔
(۴) ریٹرننگ افسر ہر کاغذ نامزدگی پر منظور یا مسترد کرنے سے متعلق اپنا فیصلہ درج کرے گا اور مسترد کرنے کی صورت میں مختصرًا اس کا سبب بھی تحریر کرے گا۔
(۵) ذیلی دفعہ ۴ کے تحت ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف کمشنر کے سامنے جو ہائیکورٹ کا چیف جسٹس ہو گا، اپیل کی جا سکے گی۔ کمشنر کے مشورے سے نامزد کردہ ہائیکورٹ کے جج کے سامنے بھی یہ اپیل کی جا سکے گی (بحوالہ حکم ۱۴، ۱۹۸۸ء)۔ اور کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ وقت کے اندر سرسری سماعت کے بعد فیصلہ کر کے حکم جاری کر دیا جائے گا جو حتمی ہو گا۔
(۶) ایسی اپیل جو ذیلی دفعہ میں بیان کردہ مدت کے دوران نہ نمٹے، مسترد شدہ سمجھی جائے گی۔
(۷) ذیلی دفعہ ۵ کے تحت کسی اپیل کی سماعت کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن یا اخبارات کے ذریعے کیے جانے والا دن اور وقت کا اعلان، دن اور وقت کے تعین کی اطلاع کے لیے کافی تصور کیا جائے گا۔‘‘
(۲۴) جانچ پڑتال کے مرحلے پر کسی مسلمان کو حاضر ہونے اور شہادت دینے سے روکنا، دراصل اسے ایسے تمام امیدواروں کے بارے میں آزادانہ اظہار رائے کے حق سے محروم کرنا ہے جو پانچ سال کی مدت کے لیے اس کے حلقہ انتخاب کی نمائندگی کے لیے منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے ایسی چھان بین کے دروازے بند کر دینے کا مطلب قرآن اور سنت کے درج ذیل احکام کی خلاف ورزی ہو گا۔
’’اے ایمان والو! خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔‘‘ (المائدہ ۸)
’’اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہشِ نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچ دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو کہ خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔‘‘ (النساء ۱۳۵)
’’شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہو گا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔‘‘ (البقرہ ۲۸۳)
(۲۵) ہم یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ عوامی نمائندگی کے قانون کی دفعہ ۱۴ جو امیدواروں کی اہلیت کو با معنی طور پر جانچنے پرکھنے کے لیے کوئی مناسب بندوبست اور سہولت فراہم نہیں کرتی اور انتخاب کرنے والے یعنی ووٹر کو چھان بین کے اس پورے عمل سے باہر رکھتی ہے، قرآن پاک اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔
(۲۶) آخر میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ قانون عام انتخابات کے مرحلے میں، جہاں علاقے کے ووٹروں کے سامنے (جن کی تعداد دو لاکھ یا اس سے زائد ہوتی ہے) صرف یہ چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ متعدد امیدواروں کے مجموعے میں سے کون کامیاب ہونے کی صورت میں ان کے لیے مفید ثابت ہو گا یا کوئی بھی نہیں ہو گا، نااہل لوگوں کے اوپر آنے کا راستہ صاف کرتا ہے۔ ووٹر جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے اس کے سماجی اور تعلیمی حالات کے پیش نظر اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ۱۸ سال یا اس سے زائد عرصہ سے زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کے سوا کسی اور چیز کو اپنے فیصلے کی بنیاد بنائے گا۔ یا اس کی رائے کو متاثر کرنے کے لیے دولت اور پروپیگنڈے کے بل پر جو انتخابی مہم چلائی جاتی ہے اس کی پیدا کردہ کشمکش اور دباؤ کے باوجود وہ کسی دیانت دار امیدوار کا انتخاب کر سکے گا۔ مزید یہ کہ ووٹر کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے نہ اسے ایسے ذرائع حاصل ہوتے ہیں جن سے وہ کسی نشست کے لیے مقابلہ کرنے والے تمام امیدواروں کی اہلیت کے بارے میں ضروری متعلقہ معلومات جمع کر سکے۔ یہ کہنا قطعی غیر معقول ہو گا کہ بالغ رائے دہی کے نظام میں ایک ایسے بیمار معاشرے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جہاں مطالعہ کا شوق رکھنے والے خال خال پائے جاتے ہیں اور خواندگی کا تناسب بمشکل ۲۵ فیصد ہے، کسی ایسے انتہائی مہارت کے حامل فورم کا متبادل ہو سکتا ہے جس کا مقصد شورٰی جیسے ادارے کی رکنیت کے امیدواروں کی صفات اور صلاحیتوں سے متعلق پیچیدہ سوالات کی مثبت شواہد اور ثبوت کی بنیاد پر تحقیق کرنا ہو۔
(۲۷) اس سلسلے میں حضرت عمرؓ کا طریقہ، جس پر انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے عمل کیا، پیش کیا گیا۔ اس کی تفصیلات یوں بیان کی گئیں کہ اپنی وفات سے کچھ پہلے خلیفہ نے ایسے چھ اصحابؓ کی ایک فہرست بنائی جو اپنی خدا ترسی اور دیانت و امانت کے حوالے سے انتہائی اچھی شہرت اور امارت کے لیے متعین بنیادی اوصاف کے پوری طرح حامل تھے، خلیفہ کا انتخاب اس فہرست میں سے ہونا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ہدایت کی کہ ان ناموں پر عام لوگوں کے سامنے بات کی جائے اور رائے عامہ کا رجحان معلوم کیا جائے۔ اس طرح سے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان چھ مجوزہ اصحاب میں، جن میں سے کوئی بھی اس منصب کے حوالے سے اپنے اندر کوئی کمی نہیں رکھتا تھا، کون عام لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے؟ اس واقعے کو قدرے تفصیل سے نقل کر دینا دلچسپی سے خالی نہیں ہو گا۔
حضرت عمرؓ نے اپنے بعد چھ آدمیوں کو خلیفہ ہونے کے لیے نامزد کیا جو یہ تھے: حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ اور فرمایا ان چھ آدمیوں میں سے ایک کو خلیفہ کے لیے منتخب کیا جائے۔ حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد ان چھ آدمیوں میں مشورے ہوتے رہے کہ ان میں سے ایک کو متفقہ طور پر نامزد کر دیا جائے اور باقی اس پر بیعت کر لیں۔ حضرت زبیر بن عوامؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ نے اپنے نام اپنی خوشی سے واپس لے لیے۔ پھر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف، سرداروں کی رائے، مسلمانوں اور ان کے سرداروں کی رائے کو متفرق اور مجتمع طور پر ایک دوکہ اور اجتماعی رنگ میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اکٹھا کرنے لگے۔ حتٰی کہ آپ پردہ نشین عورتوں کے پردہ میں ان کے پاس گئے اور مدرسے کے لڑکوں اور مدینہ کی طرف آنے والے سواروں اور بدوؤں سے بھی تین دن و رات کی مدت میں دریافت کیا۔ مگر دو اشخاص نے بھی حضرت عثمانؓ بن عفان کے تقدم میں اختلاف نہ کیا۔
فجر کی نماز کے وقت حضرت عبد الرحمٰنؓ نے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو اپنے پاس بلوایا اور دونوں کے ساتھ مسجد کی طرف چلے گئے، اور حضرت عبد الرحمٰنؓ نے وہ عمامہ پہنا ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا تھا اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور ’’الصلوٰۃ جامعۃ‘‘ کا اعلان کر دیا گیا اور مسجد لوگوں سے بھر گئی حتٰی کہ لوگوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے سے پیوستہ ہو گئے اور حضرت عثمانؓ کو لوگوں کے آخر میں بیٹھنے کو جگہ ملی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰنؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چلے اور طویل قیام کیا اور طویل دعا کی جسے لوگوں نے نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو! میں نے پوشیدہ اور اعلانیہ تمہاری آرزو پوچھی ہے اور میں نے تم کو ان آدمیوں کے برابر کسی کو قرار دیتے نہیں دیکھا۔ یا حضرت علیؓ ہوں یا حضرت عثمانؓ ہوں۔ اے علی! میرے پاس آؤ۔ حضرت عبد الرحمٰنؓ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا کہ آپ کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے فعل پر بیعت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اپنی جہد و طاقت پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور فرمایا اے عثمان! میرے پاس آؤ۔ اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہی سوال کیا اور حضرت عثمانؓ نے جواب دیا، ہاں، اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمانؓ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت علیؓ سمیت سب نے حضرت عثمانؓ پر بیعت کر لی۔ (خلاصہ تاریخ ابن کثیر ۔ اردو ترجمہ ج ۷ ص ۲۸۹ ۔ مطبوعہ کراچی)
اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ؓ نے اس منصب کے لیے بنیادی اور اساسی صلاحیتوں اور اوصاف کی جانچ پڑتال کا معاملہ عام ووٹروں کی صوابدید پر نہیں چھوڑ دیا تھا۔
(۲۸) مذکورہ بالا قرآنی احکام کی روح، آئین کے آرٹیکل ۶۲ اور ۶۳ اور اس کے ساتھ خود عوامی نمائندگی کے قانون کی دفعہ ۹۹ میں بڑی حد تک سمو دی گئی ہے۔
(۲۹) یہ بات بڑے پرزور انداز میں کہی گئی کہ آئین میں قرآنی احکام کی شمولیت، لیکن ان کے نفاذ کے لیے بنائے جانے والے قانون میں ان قرآنی احکام اور آئینی تقاضوں سے صرفِ نظر، امت اور شریعت کے ساتھ ایک ظالمانہ مذاق ہے۔ شورٰی کی تشکیل کا بنیادی فلسفہ امت میں سے بہترین اور سب سے زیادہ متقی شخص کا انتخاب ہے جو اولوالامر کی حیثیت سے کام کر سکے، یا اولوالامر کا مشیر بن سکے۔ لفظ شورٰی کے لغوی معنی شہد کے چھتے سے شہد نکالنے کے ہیں۔ بھلا شہد کے چھتے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیڑوں مکوڑوں کے حوالے کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی اہمیت کی بات یہ ہے کہ جانچ پڑتال کے مرحلے میں ارکانِ شورٰی کے بارے میں پوری تحقیق کی جاتی ہے اور صرف وہ لوگ ایوانِ مشاورت میں لائے جاتے ہیں جو اس منصب کے لیے پوری طرح موزوں پائے گئے ہوں۔ شورٰی کو ایسے لائق اور باصلاحیت افراد کا مرکز ہونا چاہیئے جن میں سے ہر ایک کو امت کے دو تین لاکھ افراد کی جانب سے قابلِ اعتماد ہونے کی سند مل چکی ہو۔
(۳۰) چونکہ آئین میں پہلے ہی شورٰی کے امیدواروں کی اہلیت کی یہ شرائط موجود ہیں اور ان کے نفاذ کے لیے طریق کار کے تعین کا معاملہ مقننہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، لہٰذا آئین کے تقاضوں کی مؤثر طور پر تکمیل کے لیے متعلقہ قانون میں اس طرح ترمیم ہونی چاہیئے کہ یہ با معنی ہو سکے۔ ہر امیدوار کی اہلیت کو جانچنے کی خاطر پہلے کھلی عدالت میں تحقیقات کے لیے اعلٰی عدالتوں کے سابق یا برسرکار ججوں، یونیورسٹیوں کے ماہرینِ تعلیم اور اسلامی اسکالروں سمیت ممتاز افراد اور معززین پر مشتمل اسکریننگ کمیٹی یا ٹربیونل کی تشکیل عمل میں آنی چاہیئے، اور جو کوئی بھی شہادت پیش کر کے ٹربیونل یا اسکریننگ کمیٹی کی مدد کرنا چاہے اسے ایسا کرنے سے روکا نہیں جانا چاہیئے۔
(۳۱) درخواست گزاروں کا دوسرا حملہ ’’عوامی نمائندگی کے قانون مجریہ ۱۹۷۶ء‘‘ کی دفعہ ۵۲ پر تھا جو اس طرح ہے:
’’۵۲۔ الیکشن پٹیشن ۔۔۔
(۱) کوئی الیکشن اس وقت تک متنازعہ نہیں کہلائے گا جب تک اس کے بارے میں کسی امیدوار کی طرف سے پٹیشن داخل نہ کی جائے۔
(۲) سرکاری گزٹ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کے نام کی اشاعت کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن پٹیشن کمشنر کو درخواست کے مصارف کے لیے ضمانت کے طور پر نیشنل بینک کی کسی بھی شاخ یا ٹریژری میں متعین کھاتے کے تحت کمشنر کے نام ایک ہزار روپیہ جمع کرانے کی رسید کے ساتھ پیش کر دینی چاہیئے۔‘‘
(۳۲) کہا گیا ہے کہ یہاں پھر اسلامی فکر کی اصل روح کو قتل کر کے مغرب کے سیاسی افکار کے تفنس کو ابھارا گیا ہے۔ منتخب امیدوار کو ووٹروں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، ووٹر اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے امین اور معتمد ہونے کی حیثیت سے اسے ہر ایسے شخص کے سامنے جوابدہ ہونا چاہیئے جس نے اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہو۔ لیکن یہ دفعہ اسے صرف اپنے حریف ہی کے مقابل رکھتی ہے کیونکہ صرف وہی اس کے خلاف انتخابی عذرداری داخل کر سکتا ہے۔ آخر ان ووٹروں کے لیے انتخابی نتائج کے تعلق سے کسی کردار کا انکار کیوں کیا جاتا ہے جن کا معتمد ہونے کا یہ امیدوار دعوٰی کرتا ہے اور انہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے حق سے کیوں محروم کر دیا گیا ہے؟
(۳۳) شروع سے آخر تک اس عمل سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ دو سیاسی جانوروں کی لڑائی ہو جس میں ووٹروں کے پورے مجمع کا کام محض تماشائی بنے رہنا اور مقابلے کے خاتمے پر صرف اس بات کا اعلان کرنا ہو کہ جیتنے والا کون ہے اور ہارنے والا کون۔ یہ صورت حال اس اصل مقصد ہی کو ختم کر دیتی ہے جس کی خاطر یہ پوری مشق کی جاتی ہے۔ اس طرح امانت اور امین کا معاملہ دو افراد کے درمیان ذاتی لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
(۳۴) استدلال کیا گیا کہ سامنے آ کر بددیانت اور ناپسندیدہ امیدوار کو، جو ممکن ہے ناجائز ذرائع اختیار کر کے کامیاب ہو گیا ہو، بے نقاب کرنا ہر ایک کا حق ہونا چاہیئے۔ شاطر اور بارسوخ فاتح کے لیے شکست خوردہ امیدوار کو عدالت جانے سے روکنا اور یوں حلقہ انتخاب کے تین لاکھ ووٹروں کے سر پر سوار رہنا زیادہ مشکل نہیں ہو گا۔ آخر ایک ایسے شخص کو ان ووٹروں پر مسلط رہنے کی اجازت کیوں دی جائے جو اسے پسند نہیں کرتے۔
(۳۵) اس لیے ضروری ہے کہ ’’عوامی نمائندگی کے قانون مجریہ ۱۹۷۶ء‘‘ کی دفعہ ۵۲ میں اس طرح ترمیم کی جائے کہ تمام ووٹروں کو (اس امیدوار کے خلاف عدالتی کارروائی کا) بھرپور موقع مل سکے جو ان کے ٹکٹ پر پارلیمنٹ کے ایوان میں جا پہنچا ہو۔ کوئی امیدوار الیکشن پر اعتراض کرے یا نہ کرے، وہ انتخابی عذرداری داخل کرے یا نہ کرے، اس بات کو یقینی بنانا بہرحال ووٹر کا حق ہے کہ اس کی نمائندگی ایک دیانتدار آدمی کی جانب سے کی جا رہی ہے جس نے انتخاب بوگس ووٹنگ، ناجائز طریقوں یا اپنے حریفوں کے خلاف سازش کر کے نہیں بلکہ جائز ذرائع سے جیتا ہے۔ ہر ووٹر کو یہ حق مہیا کیے بغیر یہ دفعہ قرآن اور سنت کے خلاف رہے گی۔
(۳۶) اس دلیل کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ارکانِ شورٰی کو، جنہیں ان ووٹروں کا امین ہونے کی حیثیت حاصل ہے جنہوں نے انہیں اوپر بھیجا ہے، مستقل طور پر اپنے رائے دہندگان کی نگرانی میں رہنا اور اپنے ہر اقدام کے لیے ان کے سامنے جوابدہ ہونا چاہیئے۔ کسی بھی وقت جب کوئی رکن کوئی غلط قدم اٹھائے تو ہر ووٹر کو اسے کھینچ کر اس سے وضاحت طلب کرنے کے قابل ہونا چاہیئے۔ یہ اختیار غیر محتاط اور کھلنڈرے ارکانِ شورٰی کے لیے ایک رکاوٹ اور سب کے لیے ایک انتباہ ہو گا کہ انہیں ہمیشہ ہر قدم ناپ تول کر اٹھانا ہے۔ اس دلیل کی تائید میں خلیفۂ اول حضرت ابوبکرؓ کا پہلا خطبہ اور حضرت عمرؓ کے واقعات پیش کیے گئے۔ ان دونوں کا یہاں نقل کر دینا فوری حوالے کے لیے سودمند ہو گا۔
حضرت ابوبکرؓ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا:
’’اے لوگو! میں تمہارے اوپر حکمران مقرر کیا گیا ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں غلطی کروں تو تم اس کو درست کر دو، اور اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرو۔ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے ضعیف میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ ان شاء اللہ میں اس کا حق دلوا دوں۔ تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ کوئی قوم اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اللہ ان پر فقر مسلط کر دیتا ہے۔ برائیاں پھیل جاتی ہیں اور مصیبتیں آجاتی ہیں۔ میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں ہے۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔‘‘ (مصنف عبد الرزاق ج ۱۱ ص ۳۳۶)
حضرت عمرؓ کی خلافت کے چند واقعات:
(۱) ایک شخص نے آپ سے بھرے مجمع میں کہا کہ عمرؓ خدا سے ڈرو۔ وہ بار بار اس جملہ کو دہرائے چلا گیا تو مجمع میں سے ایک شخص نے اس سے کہا کہ اب بس بھی کرو تم بہت کہہ چکے۔ حضرت عمرؓ نے اسے روکا اور کہا کہ نہیں اسے کہنے دو، اگر یہ ایسی بات نہ کہیں تو سمجھ لو کہ ان میں خیر کا ذرہ تک نہیں رہا، اور اگر ہم اسے نہ سنیں تو سمجھ لو کہ ہم میں خیر کی رمق تک نہیں رہی۔
(۲) ایک دن آپ نے برسر منبر کہا کہ صاحبو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، تلوار زمام سے نکالی اور کہا کہ ہم تمہارا سر اڑا دیں گے۔ آپ نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ کیا تو میری شان میں یہ بات کہتا ہے؟ اس نے نہایت سکون سے کہا کہ ہاں تمہاری شان میں۔ آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عمر بھی کج رو ہو جائے تو وہ اس کا سر اڑا دیں۔
اور یہ سر اڑا دینے کی بات تو خود آپ ہی نے انہیں بتائی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک ٹھیک چلے تو لوگوں کو چاہیئے کہ اس کی اطاعت کریں لیکن اگر وہ غلط راستہ اختیار کرے تو اسے قتل کر دینا چاہیئے۔ حضرت طلحہؓ پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو اسے معزول کر دینا چاہیئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قتل کر دینا، بعد میں آنے والوں کے لیے زیادہ عبرتناک ہو گا۔
(۳) یمنی چادریں آئیں تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر دے دی۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور حسبِ معمول مجمع سے کہا کہ ’’اسمعوا واطیعوا‘‘ سنو جو کچھ میں کہتا ہوں اور پھر اس کی اطاعت کرو۔ مجمع سے آواز آئی، ہم نہ تمہاری سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ کہنے والے حضرت سلمان فارسیؓ تھے۔ سربراہ مملکت منبر سے نیچے اتر آئے اور کہا کہ ابو عبد اللہ کیا بات ہے؟ کہا عمر! تم نے دنیا داری برتی ہے۔ تم نے ایک ایک چادر تقسیم کی تھی اور خود دو چادریں پہن کر آئے ہو۔ فرمایا، عبد اللہ بن عمر کہاں ہیں؟ حاضر ہوں امیر المومنین! فرمایا، بتاؤ ان میں سے ایک چادر کس کی ہے؟ عرض کیا، میری ہے امیر المومنین! آپ نے حضرت سلمانؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا ابو عبد اللہ! تم نے جلدی کی جو بات پوچھے بغیر احتجاج کر دیا، میں نے اپنے میلے کپڑے دھوئے تھے، باہر آنے کے لیے ایک چادر کافی نہیں تھی اس لیے میں نے (اپنے بیٹے) عبد اللہ سے چادر مانگ لی تھی۔ حضرت سلمانؓ نے کہا، ہاں اب کہیئے یا امیر المومنین! ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ آپ خود اپنا یہ قول کیسے بھول سکتے تھے؟
(۳۷) ہماری رائے میں یہ انتہائی مناسب اور پسندیدہ بات ہے کہ اسکریننگ کمیٹی یا الیکشن کمیشن کو ایسی کسی بھی شکایت کو نمٹانے کا اختیار دیا جانا چاہیئے جو رکن شورٰی کی کسی بدعنوانی یا غیر اخلاقی رویے کو ریکارڈ پر لانے کے خواہشمند اس کے حلقۂ انتخاب کے کسی ممبر یا کسی دوسرے فرد کی طرف سے کی گئی ہو۔ اگر الزامات درست ثابت ہوں تو کمیٹی کو متعلقہ رکن کو نا اہل قرار دینے اور شورٰی کی نشست سے محروم کر دینے کا اختیار حاصل ہونا چاہیئے۔
(۳۸) اس کے بعد انتخابی مصارف سے متعلق نمائندگی کے قانون کے چھٹے باب کی دفعات ۴۸، ۴۹، ۵۰ اور ۵۱ کے مجموعے اور اسی قانون کی ڈپازٹ سے متعلق دفعہ ۱۳ پر سخت اعتراض کیا گیا۔ اس اعتراض کے دو پہلو تھے:
اولاً یہ استدلال کیا گیا کہ دفعہ ۴۹ کی شق ۲ کہتی ہے کہ ’’امیدوار کے سوا کوئی بھی شخص ایسے امیدواروں کے کسی انتخابی خرچ کا مجاز نہیں ہو گا‘‘۔ اس طرح لوگوں کے کسی گروپ یا سیاسی جماعت کو، جس نے آبادی کے وسیع تر مفاد میں کسی امیدوار کو کھڑا کیا ہو، کسی بھی انتخابی خرچ سے روک دیا گیا ہے۔ شریعت کے نقطۂ نگاہ سے الگ ہٹ کر دیکھا جائے تب بھی سوچ کے اس انداز سے زیادہ مکروہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص اقتدار کے حصول کے لیے رقم خرچ کرے۔ آخر ایک دیانتدار اور بے غرض آدمی اس مقصد کے لیے کوئی بھی رقم کیوں خرچ کرے؟ ایک خود غرض اور عہدے کا حریص شخص ہی، اگر وہ قومی اسمبلی کی سیٹ کا بھوکا ہے تو ۵ لاکھ روپے اور اگر صوبائی اسمبلی کی نشست پر مطمئن ہے تو تین لاکھ روپے داؤ پر لگائے گا۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اقتدار کی طلب رکھنے والا کوئی شخص جو کرسیٔ اقتدار کی شکل میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے خطیر رقم خرچ کرنے پر تیار ہو، یقیناً بہت سی خودغرضانہ خواہشات رکھتا ہو گا۔ انسانیت کی خدمت اور عوام کی بہتری کے کسی احساس کے مقابلے میں لالچ اور اغراض کے جذبات اس کے دل میں کہیں زیادہ موجزن ہوں گے۔ اپنے انتخاب کے بعد اسے پہلی فکر ان نقصانات کو پورا کرنے کی ہو گی جو انتخابی مہم کے دوران اس نے برداشت کیے ہوں گے۔ یہ بات شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ سرکاری منصب کو خدا ترسی اور اخلاص کے بجائے دولت اور وسائل کے بل پر حاصل کرنے کی چھوٹ دے دی جائے۔
(۳۹) اگر ایک امیدوار کو رائے دہندگان کے فیصلے پر پیسے کی قوت سے اثرانداز ہونے اور ان کی بیعت اور حمایت کو دولت سے خریدنے کی چھوٹ دے دی جائے تو ایک غریب آدمی، جو ہو سکتا ہے کہ خلوص اور تقوٰی کے لحاظ سے اس شخص سے ہزاروں گنا بہتر ہو لیکن اپنے حریف کے مقابلے میں ایسے مؤثر وسائل مہیا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، کبھی بھی شورٰی میں پہنچ کر لوگوں کی خدمت کرنے کے اپنے جذبے اور اپنی آرزو کو پورا نہیں کر سکے گا۔
(۴۰) ہماری رائے میں دفعہ ۴۹ شریعت کے خلاف اور درج ذیل آیات و احادیث سے براہِ راست متصادم ہے:
’’اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار (کی نعمتوں) کا کفران کرنے والا (یعنی ناشکرا) ہے۔‘‘ (الاسراء ۲۶ و ۲۷)
’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسٰی اشعریؓ سے فرمایا، خدا کی قسم! ہم اس حکومت کے منصب پر ایسے شخص کو ہرگز مقرر نہیں کریں گے جو اس کا طالب ہو اور نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کا حریص ہو۔‘‘ (بخاری، کتاب الاحکام ص ۱۰۵۸)
’’حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنی حکومت کے کسی کام میں ایسے شخص کو استعمال نہیں کرتے جو اس کا ارادہ رکھتا ہو۔‘‘ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۳ ۔ اردو ترجمہ مطبوعہ کراچی)
’’حضرت ابوبکرؓ سے ماثور ہے کہ آپؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت کے بارے میں دریافت کیا تو حضورؐ نے جواب دیا، اے ابوبکر! وہ اس کے لیے نہیں ہے جو اس پر ٹوٹا پڑتا ہو، وہ اس کے لیے ہے جو اس سے بچنے کی کوشش کرے نہ کہ اس کے لیے جو اس پر جھپٹے۔ وہ اس کے لیے ہے جس سے کہا جائے کہ یہ تیرا حق ہے، نہ کہ اس کے لیے جو خود کہے کہ یہ میرا حق ہے۔‘‘ (قلقشندی صبح الاعشی ج ۱ ص ل ۲۴۰)
(۴۱) ہم یہ سفارش کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ جو امیدوار اسکریننگ کے عمل سے گزرنے کے بعد مقررہ معیارِ اہلیت کے مطابق قرار پائیں انہیں رائے دہندگان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور جہاں یہ ممکن نہ ہو وہاں دوسرے ذرائع سے متعارف کرایا جائے۔ ہر امیدوار کے لیے وقت مختص کیا جانا چاہیئے اور ہر امیدوار کے حامیوں اور مددگاروں کی باہمی گفتگو (پینل ڈسکشن) کے ذریعے امیدواروں کو رائے دہندگان سے متعارف کرایا جانا چاہیئے۔ ہر امیدوار کو ٹی وی سے اور جہاں یہ ممکن نہ ہو وہاں الیکشن کمیشن کے زیراہتمام منعقدہ عوامی اجتماعات کے ذریعے اپنے حلقۂ انتخاب کے ووٹروں سے براہ راست خطاب کا موقع فراہم کیا جانا چاہیئے۔
(۴۲) بعض پابندیوں کے ساتھ امیدوار کے حامیوں کو پوسٹروں کے ذریعے تشہیر کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ حامیوں کی جانب سے جاری کردہ پوسٹروں اور اسی نوعیت کی دیگر چیزوں میں صرف اس امیدوار کی خوبیوں اور صفات پر تبصرہ ہونا چاہیئے جسے انہوں نے اسمبلی کے لیے نامزد کیا ہو۔ اس مرحلے پر دوسرے امیدواروں کی کردار کشی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ سب بھی اسکریننگ کمیٹی کی جانب سے مطلوبہ معیار کے مطابق قرار دیے جا چکے ہوں گے۔ اگر حریف امیدوار کے دامنِ کردار پر کوئی داغ ہو تو اسے اسکریننگ کمیٹی کے سامنے ثابت کیا جانا چاہیئے، پریس میں شائع نہیں کرنا چاہیئے۔
(۴۳) عوامی نمائندگی کے قانون کی دفعہ ۹۹ کی شق (اے) کی ذیلی شق (کے) کے حوالے سے ایک اور اعتراض ۔۔۔۔ دلیل دی گئی کہ شورٰی کو قوم کے بہتر عنصر پر مشتمل ہونا چاہیئے۔ اہلِ دانش اور پختہ تجربے کے حامل افراد کو معاشرے کے ایک ایک گوشے سے چن کر شورٰی میں لایا جانا چاہیئے، یہ امت کے اہل الرائے ہوتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو خوبی اور اہلیت قرار دیا جانا چاہیئے اسے ’’عوامی نمائندگی کے قانون‘‘ کی دفعہ ۹۹ کی شق (اے) کی ذیلی شق (کے) میں یا اسی کے مماثل ’’ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے حکم مجریہ ۱۹۷۷ء‘‘ کی دفعہ ۱۰ کی شق ۲ کی ذیلی شق ۴ میں نا اہلیت کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ یہ حصہ فوری حوالے کے لیے ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:
’’(کے) وہ پاکستان کی، یا آئین کی رو سے تشکیل پانے والے کسی ادارے، یا کسی بھی ایسے ادارے کی جو حکومتِ پاکستان کی ملکیت یا کنٹرول میں ہو، یا جس میں حکومت کا غالب حصہ یا مفاد ہو، ملازمت میں رہا ہو۔ سوائے اس کے کہ اسے ایسی ملازمت کو چھوڑے ہوئے دو سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔‘‘
(۴۴) استدلال کیا گیا کہ اعلٰی عدالتوں کے سابق ججوں، جامعات کے پروفیسروں اور دوسرے دیانتدار اور تجربہ کار ریٹائرڈ سرکاری ملازموں کو، جو دفتر خارجہ یا بیرونی مشن میں خدمات انجام دے چکے ہوں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کم از کم دو سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایسے افراد کے پاس بحیثیت رکن شورٰی اپنی صلاحیتوں اور مہارت و تجربے کے استعمال کا جو بہترین وقت ہوتا ہے اسے جبری رخصت کی نذر کر کے انہیں گھر کے اندر گوشۂ تنہائی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور دو سال کے دوران ان کی فہم و فراست کی ساری تیزی زنگ آلود ہو کر کند ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے پختہ کار اور مہارت یافتہ افراد کو شورٰی کی رکنیت کے لیے ناموزوں قرار دیے جانے کے اس رویے میں کوئی حکمت و دانش نہیں پاتے۔ تاہم بدقسمتی سے اس کے خلاف اپنی رائے کے اظہار سے زیادہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آئین کی دفعہ ۶۳ کی شق (کے) میں بھی اسے نا اہلی کی ایک وجہ کی حیثیت سے شامل رکھا گیا ہے اور آئین ہماری دسترس سے باہر ہے۔
(۴۵) بیلٹ کی رازداری سے متعلق دفعات کے پورے مجموعے خصوصاً دفعہ ۸۸ اور دفعہ ۸۹ کو بھی، جو بیلٹ کی رازداری کی شرط عائد کرتی ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی حیثیت سے چیلنج کیا گیا ہے۔ معترضین کی دلیل یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے ووٹ دینا دراصل شہادت دینا ہے اور ایک مسلمان کو اتنا جرأتمند ہونا چاہیئے کہ وہ خوف کے بغیر اور تعلقات سے بلند ہو کر سچی گواہی دے سکے۔ اس سلسلہ میں سورہ نساء کی آیت ۱۳۵ بھی پیش کی گئی:
’’اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو،
خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر
کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہشِ نفس کے پیچھے
چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچ دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا
چاہو گے تو جان رکھو کہ خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔‘‘ (النساء ۱۳۵)
(۴۶) تاہم یہ نوٹ کیا جانا چاہیئے کہ دفعات کا یہ مجموعہ دستور کے آرٹیکل ۲۲۶ میں ظاہر کی جانے والی قانون سازی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے۔ دستور کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ
آرٹیکل ۲۲۶ ۔۔۔ ’’آئین کے تحت تمام انتخابات خفیہ رائے دہی سے ہوں گے۔‘‘
(۴۷) مزید یہ کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ایک حق سے استفادے کے لیے اختیار کی جانے والی ایک احتیاطی تدبیر کو خود اس حق کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دفعات رائے دہی کے حق کے استعمال کے طریقے کو بیان کرتی ہیں۔ اس لیے رائے دہی کے اخفا کی دفعات برقرار رکھی جا سکتی ہیں لیکن اس حق کے استعمال کو منضبط کرنے کی شکل یا قاعدے کے ذریعے خود اس حق کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی یہ کہ اگر ایک ووٹر غیر ارادی طور پر رازداری کے سخت قوانین کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو اسے رائے دہی سے محروم نہیں کیا جانا چاہیئے اور اس کا ووٹ غیر درست قرار نہیں دیا جانا چاہیئے۔
(۴۸) اوپر کی تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوامی نمائندگی کے قانون کی دفعات ۱۳، ۱۴، ۴۹، ۵۰ اور ۵۲ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ رائے دہی کی رازداری سے متعلق دفعات ۸۸ اور ۸۹ برقرار رکھی جا سکتی ہیں لیکن دفعہ ۳۸ (۴) (سی) (۱۱) جس کے تحت ایک جائز ووٹ محض اس لیے گنتی سے خارج کر دیا جاتا ہے کہ ووٹر رازداری ملحوظ نہیں رکھ سکا، قرآن و سنت سے متصادم ہے (النساء ۱۳۵)۔ ’’عوامی نمائندگی کے قانون مجریہ ۱۹۷۶ء‘‘ اور ’’ایوان ہائے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے (انتخابی) حکم مجریہ ۱۹۷۷ء‘‘ میں، اس فیصلے کے مطابق، صدرِ پاکستان کی جانب سے ۳۱ دسمبر ۱۹۸۹ء تک ترمیم کر دی جانی چاہیئے۔ ۳۱ دسمبر ۱۹۸۹ء کے بعد دفعات ۱۳، ۱۴، ۴۹، ۵۰، ۵۲ اور ۳۸ (۴) (سی) (۱۱) غیر مؤثر ہو جائیں گی۔
دستخط
جسٹس عبادت یار خان۔ چیف جسٹس گل محمد خان۔ جسٹس شجاعت علی قادری۔ جسٹس مفتخر الدین۔ جسٹس فدا محمد خان
اسلام آباد ۔ ۱۶ اکتوبر۱۹۸۹ء
نوٹ
وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلہ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے ابتدائی سماعت کے بعد وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلہ کو ان ریمارکس کے ساتھ عارضی طور پر معطل کر دیا ہے کہ چونکہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور فیصلہ کے بعض پہلو تفصیلی بحث کے متقاضی ہیں جن کا فیصلہ انتخابات سے قبل نہیں ہو سکتا، نیز عدالتِ عظمٰی انتخابات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ عارضی طور پر معطل کیا جاتا ہے۔ (مدیر الشریعہ)
پردہ اور بائبل
مسیحی مذہبی راہنماؤں کی توجہ کے لیے
محمد عمار خان ناصر
کلامِ الٰہی قرآن پاک میں ارشاد ہے:
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیھن من جلابیبھن ذٰلک ادنٰی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورًا رحیما۔ (الاحزاب ۵۹)
ترجمہ: ’’اے پیغمبر! اپنی بیبیوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیبیوں سے بھی کہہ دیجیئے کہ (سر سے) نیچے کر لیا کریں اپنے تھوڑی سی اپنی چادریں اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔‘‘ (ترجمہ حضرت تھانویؒ)
مذکورہ آیت میں پردہ کا حکم دیا گیا ہے۔ حاشیہ پر علامہ عثمانیؓ لکھتے ہیں:
’’یعنی بدن ڈھانکنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے چہرے پر بھی لٹکا لیویں۔ روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کھلی رہتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت آزاد عورت کو چہرہ بھی چھپا لینا چاہیئے۔ لونڈی یا باندی کو ضرورتِ شدیدہ کی وجہ سے اس کا مکلف نہیں کیا کیونکہ کاروبار میں حرجِ عظیم واقع ہوتا ہے۔‘‘
حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں:
’’یعنی پہچانی پڑیں کہ لونڈی نہیں بی بی ہے، صاحبِ ناموس بدذات نہیں نیک بخت ہے تو بد نیت لوگ اس سے نہ الجھیں۔‘‘
ایک دوسرے مقام میں ارشاد ہے:
وقل للمومنات یغضضن من ابصارھن ویحفظن فروجھن ولا یبدین زینتھن الا ما ظہر منھا ولیضربن بخمرھن علی جیوبھن۔ (النور ۳۱)
ترجمہ: ’’اور (اسی طرح) مسلمان عورتوں سے (بھی) کہہ دیجیئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس (موقع زینت) میں سے (غالباً) کھلا رہتا ہے (جس کے ہر وقت چھپانے میں ہرج ہے) اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔‘‘ (ترجمہ حضرت تھانویؒ)
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضھم علٰی بعض۔ (النساء)
’’مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔‘‘
آیت مذکورہ میں جہاں گھریلو مسائل و معاملات میں مرد کی برتری کا حکم ملتا ہے وہاں سیاسی، قومی اور ملکی معاملات میں بھی صرف مرد کا حکمران ہونا مسلّم قرار پاتا ہے۔ چنانچہ ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ’’الرجال قوامون‘‘ کی تفسیر ’’امرا‘‘ کے ساتھ کی ہے (تفسیر ابن جریر الطبریؒ ج ۵)۔ یہاں بھی عورت کو گھر کے اندر اور گھر سے باہر کے معاملات میں اس لیے مرد کے ماتحت رکھا گیا ہے کہ عورت میں کچھ فطری کمزوریاں ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ’’النساء حبالۃ الشیطان‘‘ کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عورت کی یہ صفت اس کے گھر سے باہر کے معاملات مثلاً حکومت و ولایت اور جہاد وغیرہ میں حقدار و مکلف نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔
عورت کے لیے پردہ اور مرد کے تابع ہونے کا حکم کتبِ سابقہ میں بھی موجود ہے۔ بائبل سے چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:
’’پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے دردِ حمل کو بہت بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہو گی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔‘‘ (پیدائش ۳ / ۱۶)
’’ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے ۔۔۔ اور جو عورت بے سر ڈھنکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سرمنڈی کے برابر ہے۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔‘‘ (اول کرنتھیوں ۱۱ / ۶۰۳)
’’اے بیویو! اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہر کی تابع ہوں۔‘‘ (افسیوں ۵ / ۲۲۔۲۴)
’’عورتیں حیادار لباس میں شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں نہ کہ بال گوندھنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے ۔۔۔۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیئے اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے۔‘‘ (۱۔تیمتھیس ۲ / ۹۔۱۲)
’’اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں۔‘‘ (۔۔۔ ۲ / ۵)
جہاں تک شرائع کا تعلق ہے بائبل عورت کو مکمل طور پر پردے کا پابند اور گھر تک محدود کر دیتی ہے لیکن عیسائیت کا قدیم مسکن مغرب بے پردگی اور آوارگی میں کچھ زیادہ ہی رسیاں تڑا گیا ہے۔ عیسائی مشنریاں عورت اور وہ بھی فحاشی اور عریانی سے مالامال جیسے خطرناک ہتھیار سے لیس ہیں۔ عورتیں ملک کے ہر محکمہ حتٰی کہ مذہبی راہنماؤں کے ساتھ بھی نوجوان سسٹرز اور ماوا میں تبلیغ کے بہانے مصروف العمل ہیں جو بائبل کے صریح فرامین کے خلاف ہے۔ تبلیغ کرنا عورت کو روا نہیں ہے ۱۔تیمتھیس ۲ / ۱۲۰۹ سے یہ واضح طور پر منصوص ہے۔ اس بات کا مسیحی علماء کو بھی اقرار ہے کہ یورپ کی عورت آزادی میں حد سے بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پادری آر بسن لکھتے ہیں:
’’یہ قابل افسوس بات ہے کہ مغربی ممالک کی عورتیں جن کو حد سے زیادہ آزادی دی گئی ہے قدرت کے خلاف زندگی بسر کرتی ہیں۔‘‘ (حقوق و فرائض نسواں ۔ مصنفہ ڈاکٹر پادری جے ایچ آربسن ایم ڈی ۔ مطبوعہ ۱۹۲۸ء ص ۳۱)
مزید لکھتے ہیں:
’’مرد عورت سے زیادہ قدآور اور طاقتور ہوتا ہے لہٰذا وہ محنت و مشقت کے کاروبار کرنے کے زیادہ قابل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے اور محنت و مشقت کا کام اپنے ذمہ لے۔ عورت کا کام مرد کے کام کی نسبت زیادہ مشکل اور نازک ہے اور اس کا اثر رگوں اور پٹھوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ذرا عقل اور سمجھ کو استعمال کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ عورت کے ساتھ نہایت بے انصافی کی گئی ہے کہ جس حال کہ اس کی طاقت کو اس الٰہی مقصد کے لیے محفوظ رکھا جانا چاہیئے تھا کہ جس کے لیے وہ خلق کی گئی اس کو دنیا کے سخت اور کٹھن معاملات میں صرف کیا گیا ہے۔‘‘ (ص ۱۶)
اب یہ مشکل اور کٹھن کام نہیں تو اور کیا ہے کہ مغرب سے عورتوں کو دور دراز کے ممالک میں تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے، انہیں گھر بار سے دور رکھا جاتا ہے اور نجانے کیا کیا بھاری ذمہ داریاں اس نازک وجود پر ڈالی جاتی ہیں۔ مسیحی مذہبی راہنماؤں سے گزارش ہے کہ بائبل کی تبلیغ کے سلسلہ میں کم از کم بائبل کے احکام کا لحاظ تو کر لیا جائے اور عورت کی بے پردگی، فحاشی اور عریانی کے خلاف عَلم جہاد بلند کیا جائے۔
آپ نے پوچھا
ادارہ
کیا حضرت عمرؓ نے احادیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا؟
سوال: منکرینِ حدیث کا کہنا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے دورِ خلافت میں احادیث کی روایت سے منع فرمایا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ (عبد الکریم، کوئٹہ)
جواب: یہ بات درست نہیں ہے اور جو روایات ایسی منقول ہیں ان کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو منکرینِ حدیث بیان کرتے ہیں، بلکہ اصل روایات کو ملاحظہ کیا جائے تو مطلقاً منع کرنے کا حکم ہمیں نہیں ملتا بلکہ اس میں روایات کو بکثرت بیان کرنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ عراق کی طرف روانہ کردہ وفد کو حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ
’’فلا تصدوھم بالاحادیث فتشغلوھم جودوا القراٰن واقلوا الروایۃ عن رسول اللہ‘‘ (تذکرۃ الحفاظ للامام ذہبیؒ ج ۱ ص ۴)
ترجمہ: ’’انہیں (اہل عراق کو) احادیث کے ذریعے (قرآن سے) نہ روک دینا کہ تم انہیں (احادیث کے ساتھ ہی) مشغول کر دو۔ قرآن کو اچھا کر کے (پڑھو) اور (احادیث) بیان کرنا کم کر دو۔‘‘
اس کی وجہ حافظ ذہبیؒ یہ بیان کرتے ہیں کہ
وقد کان عمر من وجلہ ان یخطیٔ الصاحب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرھم ان یقلوا الروایۃ عن نبیھم ولئلا یتشاغل الناس بالاحادیث عن حفظ القراٰن۔
ترجمہ: ’’عمرؓ نے اس خوف سے کہ رسول اللہ کی طرف بہتان منسوب ہو جائے گا، اصحابؓ کو حکم دیا کہ احادیث کی روایت کو کم کر دیں اور تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر احادیث کے ساتھ مشغول نہ ہو جائیں۔‘‘
علاوہ ازیں اگر حضرت عمرؓ کی مراد روایت حدیث سے مطلقاً منع کرنا ہوتی تو لازماً آپ خود بھی احادیث کی روایت نہ کرتے حالانکہ ایک قول کے مطابق حضرت عمرؓ سے ۵۳۷ احادیث مروی ہیں (تاریخ عمرؓ بن الخطاب للامام ابو الفرج جمال الدین ابن الجوزیؒ ص ۱۷۳)۔ پھر حضرت عمرؓ ایک عام راوی نہیں بلکہ پختہ کار محدث تھے۔ حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں:
وھو الذی من للمحدثین التثبت فی النقل۔ (تذکرہ ص ۶ ج ۱)
ترجمہ: ’’حضرت عمرؓ نے ہی محدثین کو نقلِ حدیث میں ثابت قدمی کی راہ بتلائی۔‘‘
حافظ ذہبیؒ نے چند واقعات نقل کیے ہیں جو منکرینِ حدیث کے دعوے کے ابطال پر حجتِ قاطعہ ہیں۔ یہاں پر ان میں سے ایک نقل کیا جاتا ہے: ابو موسٰی الاشعریؓ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے گھر آئے اور باہر کھڑے ہو کر تین دفعہ سلام کیا لیکن جواب نہ ملنے پر واپس ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا اور پوچھا کہ آپ واپس کیوں لوٹ گئے تھے؟ ابو موسٰیؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تین دفعہ سلام کرنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ آیا کرو۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایک اور گواہ لاؤ ورنہ میں سزا دوں گا۔ تو ابو موسٰیؓ نے صحابہ میں سے ایک آدمی کو بطور گواہ کے پیش کر دیا یعنی حضرت عمرؓ نے ایک راوی کے ہوتے ہوئے (جو ثقہ بھی تھے) گواہ طلب کیا اور اس کے بعد انہیں اطمینان ہوا۔ الغرض منکرینِ حدیث کا مذکورہ دعوٰی بدلائل قاطعہ و براہین ساطعہ باطل ہے۔
امام ابن حجرؒ کون تھے؟
سوال: علمِ حدیث کے حوالہ سے ابن حجرؒ کا نام اکثر سننے اور پڑھنے میں آتا ہے۔ یہ بزرگ کون ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے؟ (محمد احمد، گوجرانوالہ)
جواب: امام ابن حجرؒ کا نام احمد بن علی ہے اور آٹھویں، نویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ۷۷۳ھ میں کنانۃ (عسقلان) کے مقام پر پیدا ہوئے پھر مصر چلے گئے۔ مسلکاً شافعی ہیں، تمام علوم و فنون خصاصاً علمِ حدیث میں مہارتِ تامّہ رکھتے تھے۔
برع فی الحدیث و تقدم فی جمیع فنونہ (لحظ الالحاظ بذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۳۸۱)
’’حدیث کے فن میں کامل اور دوسرے تمام فنون میں سب سے بڑھ کر تھے۔‘‘
وقد غلق بعدہ الباب و ختم بہ ھذا الشان (ص ۳۸۲)
’’آپ کے بعد اس پایہ کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔‘‘
ابن حجرؒ کی زیادہ تر تصنیفات علمِ حدیث اور اسماء الرجال پر ہیں۔ علمِ حدیث میں صحیح بخاری کی شرح ’’فتح الباری‘‘ ہر دور میں متداول اور متقدمین و متاخرین کا ماخذ رہی ہے۔ جبکہ علمِ رجال میں تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، لسان المیزان، الاصابۃ الدرر الکامنۃ اور دیگر کتب دوسری تمام کتبِ رجال سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں تعلیقات و تخریجات سو (۱۰۰) سے بڑھ کر ہیں (ص ۳۸۱)۔ قریباً ایک ہزار مجالس میں املاء کروایا، متعدد مقامات پر تدریس کی اور بالآخر ذی الحجہ ۸۵۲ھ میں وفات پا گئے۔ ابن حجرؒ کے جنازہ کے موقع پر بارش ہو گئی تو کسی عقیدت مند نے کہا
قد کمبت السحب علی قاضی القضاۃ بالمطر
وانہدم الرکن الذی کان مشیدًا من حجر
’’قاضی القضاۃ کی وفات پر بادل بارش کے ساتھ روئے اور پتھر جیسا مضبوط عالم گر گیا۔‘‘
جاحظیہ کون تھے؟
سوال: جاحظیہ کون تھے اور ان کے عقائد کیا تھے؟ (محمد عبد اللہ، وہاڑی)
جواب: جاحظیہ، معتزلہ کی ایک شاخ ہیں۔ یہ لوگ عمرو بن بحرین الجاحظ کے پیروکار تھے جو معتصم باللہ اور متوکل علی اللہ عباسی خلفاء کے دور (دوسری صدی ہجری کے نصف اول) میں ایک بڑا عالم تھا۔ ان کے چند ایک عقائد کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے جو جمہور معتزلہ سے جدا ہیں:
(۱) عقائد (علمِ الٰہی) بالکلیۃ ضروری ہیں اور ہر انسان ان کو طبعی طور پر جانتا ہے حتٰی کہ خدا اور نبی کا مفہوم بھی جانتا ہے۔
(۲) اہلِ جہنم کو جسمانی سزا نہیں ملے گی بلکہ آگ ان کو اپنے اندر جذب کر لے گی اور وہ آگ ہی بن جائیں گے۔
(۳) تمام صفاتِ باری تعالٰی (علم، حیات، ارادہ، قدرت، سمع، بصر وغیرہ) کے اصلاً منکر ہیں۔
(۴) خلقِ قرآن کے بارے میں اس حد تک معتقد تھے کہ ان کے نزدیک قرآن مرد اور عورت کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔
(الملل والنحل للامام الشہرستانیؒ ج ۱ ص ۹۱ ۔ ۹۴)
لفظ ’’فارقلیط‘‘ کیا ہے؟
سوال: فارقلیط کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ (عبد الحفیظ، وزیر آباد)
جواب: فارقلیط یونانی لفظ ’’پیرکلوتوس‘‘ سے مقرب ہے اور اس کا معنی تعریف کیا ہوا یعنی ’’احمد‘‘ ہے۔ یہ لفظ انجیل یوحنا ۱۶ : ۷ ۔ ۱۵ میں بار بار استعمال ہوا ہے اور حضرت عیسٰیؑ نے آنحضرت کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی (الصف ۶) حضرت عیسٰی کی اس بشارت کو نقل کیا گیا ہے۔ عیسائی حضرات جہاں ان بشارات کے آنحضرتؐ پر اطلاق سے انکار کرتے ہیں اور ان کو روح القدس (اقنوم ثالث‘‘ کے لیے ماننے پر اصرار کرتے ہیں، اسی طرح اس لفظ کی تاویل میں کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان کے لفظ ’’پراکلی توس‘‘ سے مقرب ہے نہ کہ ’’پیرکلوتوس‘‘ سے اور ’’پراکلی توس‘‘ کا معنی ’’احمد‘‘ نہیں ہے۔ (فارقلیط از پادری وکلف اے سنگھ ص ۱۱ ۔ شائع کردہ مسیحی اشاعت خانہ لاہور)۔ تفصیلی بحث کے لیے دیکھئے ’’فارقلیط کون ہے؟‘‘ از مولانا بشیر الحسینی، شائع کردہ اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی نمبر ۵۔
تعارف و تبصرہ
ادارہ
’’روس کے ایک عظیم مجاہد امام شاملؒ‘‘
تصنیف: جناب محمد حامد
صفحات ۲۱۲ قیمت مجلد ۷۵ روپے۔ کتابت و طباعت معیاری
ملنے کا پتہ: الفلاح پبلشرز پوسٹ بکس ۳۱۲ ۔ ۲۱ فرسٹ فلور، مال پلازہ، دی مال، راولپنڈی صدر
ہماری روایتی کہانیوں میں ’’کوہ قاف‘‘ کا ذکر مہم جوئی اور تجسس خیزی کے محور کے طور پر کیا جاتا ہے اور بحیرۂ اسود اور بحیرۂ کیپسن کے درمیان شمال مغرب سے جنوب مشرق تک پھیلے ہوئے پہاڑوں کی یہ سرزمین جو قفقازاور کا کیشیا کے نام سے بھی متعارف ہے فی الواقع مہم جو اور باہمت لوگوں کا علاقہ ہے۔ روسی استعمار کی توسیع پسندی اور ہوسِ ملک گیری نے جب اپنے اردگرد کی اقوام پر جبرو تسلط کے پنجے گاڑے تو قفقازاور یا کوہ قاف کا یہ علاقہ بھی اس کی زد میں آیا اور اس خطہ کے غیور مسلمانوں نے ’’امام شامل‘‘ کی قیادت میں روسی توسیع پسندی کا آخر دم تک مقابلہ کر کے معرکہ ہائے حریت و استقلال کی عظیم تاریخ میں ایک روشن اور قابلِ تقلید باب کا اضافہ کیا۔
امام شاملؒ بنیادی طور پر نقشبندی سلسلہ کے ایک روحانی بزرگ تھے لیکن جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ صوفیائے کرامؒ کی یہ خانقاہیں ہر دور میں دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ دینی حمیت و غیرت کے سرچشمے اور حریت و جہاد کی تربیت گاہیں بھی رہی ہیں۔ امام شاملؒ نے اپنے علاقہ میں روسی افواج کے تسلط کے ساتھ ہی حریت و استقلال کا پرچم بلند کیا اور جہاد کے معرکے بپا کر کے ایک طویل عرصہ تک اس خطہ کو روسی استعمار کے مکمل قبضہ سے بچائے رکھا۔ گزشتہ صدی کے دوسرے ربع کے آغاز سے ساتویں عشرہ کے اختتام تک روسی افواج کے خلاف امام شاملؒ کی یہ گوریلا جنگ زارِ روس کی فوجوں کے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہوئی اس کا اندازہ ایک روسی جنرل ویلمینوف کے اس تبصرہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ
’’ان مہمات میں روس کی فوجوں کا جو جانی نقصان ہوا اور جتنا عظیم لشکر ان کارروائیوں میں تہہ و بالا ہو کر رہ گیا اس کی مدد سے ہم جاپان سے لے کر ترکی تک علاقہ فتح کر سکتے تھے۔‘‘
اس امر کی ضرورت تھی کہ نئی نسل کو تاریخِ اسلام کے اس عظیم مجاہد کی جدوجہد اور قربانیوں سے متعارف کرایا جائے۔ جناب (ریٹائرڈ میجر) محمد حامد تبریک و شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے زیرنظر کتاب کی صورت میں اس اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ یہ کتاب جو امام شاملؒ اور ان کی جدوجہد کے بارے میں ایک مستند اور جامع تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے، اردو کے علاوہ انگریزی، عربی اور سندھی زبانوں میں بھی چھپ چکی ہے۔ اور اس پر ریٹائرڈ میجر جنرل جناب فضل مقیم خان کے دیباچہ اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے پیش لفظ سے کتاب کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے۔
’’سعدیات‘‘ ۔ مختصر انتخابِ کلامِ سعدیؒ
انتخاب و ترتیب: مولانا صوفی عبد الحمید سواتی
صفحات ۶۰ قیمت ۱۶ روپے۔ کتابت و طباعت عمدہ
ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ
شیخ سعدیؒ کا شمار امتِ مسلمہ کے ممتاز مصلحین میں ہوتا ہے جن کے ادبی و اصلاحی جواہر پارے فارسی سے دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر عالمی ادب کا حصہ بن چکے ہیں۔ بالخصوص گلستان، بوستان اور کریما ادب و اخلاق کے ایک لازوال سرچشمہ کی حیثیت سے آج بھی نسلِ انسانی کے ایک قابل ذکر حصہ کی تعلیم و اصلاح کا ذریعہ ہیں۔
حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ العالی نے گلستان، بوستان اور شیخ سعدیؒ کی دیگر تصنیفات میں سے ایک مختصر اور حسین انتخاب زیرنظر کتابچہ کی صورت میں پیش فرمایا ہے جو بلاشبہ اصحابِ ذوق کے لیے قابلِ قدر تحفہ ہے۔
ماہنامہ ’’راہ نمائے صحت‘‘ فیصل آباد ۔ خصوصی نمبر
مدیر اعلٰی: حکیم عبد الرحیم اشرف
صفحات ۲۲۶ قیمت ۲۰ روپے
زیراہتمام: اشرف لیبارٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ۔ ۶ کلومیٹر سرگودھا روڈ، فیصل آباد
مولانا حکیم عبد الرحیم اشرف ایک مخلص اور درد دل سے بہرہ ور دینی راہنما ہونے کے علاوہ ممتاز طبیب بھی ہیں اور طبی برادری میں انہیں ایک بزرگ راہنما کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی قائم کردہ اشرف لیبارٹریز ملک کے معروف دواساز اداروں میں شمار ہوتی ہے اور ماہنامہ راہ نمائے صحت فیصل آباد محترم حکیم صاحب موصوف کی زیرادارت طبِ اسلامی کی خدمت و ترجمانی کے مشن میں مصروف ہے۔
زیرنظر شمارہ ’’خصوصی نمبر‘‘ ہے جو ملک کے ممتاز اطباء حکیم عبد المالک مجاہدؒ، حکیم فضل الٰہیؒ اور حکیم مظفر احسنؒ کی خدمات اور طبی کارناموں کے تعارف و تذکرہ کے لیے شائع کیا گیا ہے اور اس میں ان تینوں بزرگوں کے بارے میں معلوماتی مضامین شامل ہیں۔
’’حی علی الفلاح‘‘
از: مولانا محمد فیاض خان سواتی
صفحات ۱۰۰ قیمت ۱۴ روپے۔ کتابت و طباعت معیاری
ملنے کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ
حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مہتمم مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ نے ’’نمازِ مسنون‘‘ کے نام سے مسائلِ نماز پر ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی جس میں نماز سے متعلق کم و بیش تمام مسائل و احکام ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے علاوہ اختلافی امور پر احناف کے دلائل مثبت اور علمی انداز میں ذکر کر دیے۔ اس مثبت اور اصلاحی انداز کو ملک بھر میں سراہا گیا اور ’’نمازِ مسنون‘‘ کو علماء اور دیگر علیم یافتہ حلقوں میں پسند کیا گیا۔
گوجرانوالہ کے اہلِ حدیث عالم خواجہ محمد قاسم صاحب نے جو مناقشانہ مزاج اور مناظرانہ بحثوں میں خاصی شہرت رکھتے ہیں ’’حی علی الصلٰوۃ‘‘ کے نام سے ایک کتابچہ میں ’’نمازِ مسنون‘‘ کے مختلف دلائل کو رد کرنے کی کوشش کی جس پر حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ کے فرزند برادرم مولانا حافظ محمد فیاض خان سواتی مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم نے زیرنظر رسالہ میں تعاقب کیا ہے اور دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ حضرت صوفی صاحب کے بیان کردہ دلائل درست ہیں اور خواجہ صاحب موصوف کے اعتراضات کی حیثیت کج بحثی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
جریان، احتلام اور سرعتِ انزال کے اسباب اور علاج
حکیم محمد عمران مغل
حیوانات کی پیدائش کے ساتھ ہی قدرت نے بقائے نسل کے لیے توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اس میں ارزل ترین مخلوق سے اشرف المخلوق انسان تک سب مشترک ہیں۔ ہر جنس اپنی جسمانی ساخت، رسم و رواج، آب و ہوا، حالات، گرد و پیش کے تحت اس وظیفۂ حیات کو انجام دینے پر فطرتاً مجبور ہے۔ بعض ممالک میں جدید نسل کی رہنمائی کے لیے اسے تعلیم سے منسلک کیا گیا ہے لیکن ہمارے ہاں تمام جنسی کتب صرف ذہنی عیاشی تک ہی محدود ہیں ؎
اک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے
ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ
آج سے ایک دہائی پہلے لاہور سے جناب پروفیسر مظہر علی ادیب صاحب نے سکول کالج کی درسی کتب پر عالمانہ تنقید قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ اندازہ لگایا گیا کہ بعض اسباق میں آدھے سے زیادہ مواد صرف عاشقی معشوقی پر تحریر کیا ہے جسے منسوخ کیا گیا۔ یعنی ہماری بے حسی کہ نئی پود کے ہاتھوں میں کیا مواد ہے ہمیں پتہ تک نہیں۔ نظامِ تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک عام معمولی نوجوان سے بھی پوچھیں تو وہ بی پی فلم کے متعلق اس تفصیل سے بتائے گا جیسے اس نے یہی کام کرنا ہے۔
قدرت نے ان مقاصد کے حصول کے لیے توالد و تناسل میں ایک لذت کی کیفیت پنہاں رکھی ہے تاکہ ہر ذی روح اور خصوصاً حیوان انسان برضا و رغبت متوجہ رہیں۔ اسی لذت کے متوالے زنا اور دیگر فواحشات کے دلادہ ہو کر اس کے عواقب و نتائج سے بالکل بے خبر اپنی زندگی کا چراغ وقت سے پہلے گل کر لیتے ہیں اور اکثریت غیر طبعی موت مرتی ہے۔ آسمانِ طب کے ماہتاب جناب جالینوس کا ارشاد ہے کہ انسان ایک چراغ ہے اور منی اس کا تیل ہے۔ جونہی یہ تیل ختم، زندگی کا کھیل بھی ختم۔ تیل کے اس چشمہ کو اپنے ہاتھوں خشک کرنے کے بعد انسان مصنوعی اشیاء اور وسائل کی جستجو میں لگ جاتا ہے مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہی وہ منحوس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کی آپس میں توتکار ہوتی ہے جس کا بھیانک انجام اخبارات کے ذریعے خاندان میں جگ ہنسائی کا باعث بنتا ہے۔ اب بیوی مغلوب ہو گی نہ مرعوب ؎
صحت نہ ہو تو سیم و زر بیکار ہے
خوب رو بیوی پری پیکر بھی ہو تو خار ہے
آج کل جنسی حمام میں ہمارا معاشرہ اکثر ننگا نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اخبار میں نوجوانوں نے خطوط لکھے کہ ہم جریان، احتلام کی بیماری میں اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، ہماری مدد کریں۔ اس وقت ۹۸ فیصد نوجوان مبتلا تھے مگر آج ؎
شیاطیں نے چکر چلائے ہوئے ہیں
بڑے سے بڑے ورغلائے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ نے جسمِ انسانی میں بہت سی قوتیں پیدا کر کے پھر ان کے لیے الگ الگ اعضا بھی پیدا کیے ہیں جن میں پوشیدہ اعظا انتہائی حساس ہیں۔ اگر یہ قوتیں ان اعضا سے مل کر اپنا اپنا فعل ادا کرتی رہیں تو انسان اپنی طبعی عمر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے بشرطیکہ ان اعضا سے کوئی غیر فطری کام نہ لیا گیا ہو۔ اگر غیر فطری طریقہ سے ان میں کوئی نقص واقع ہو گیا تو پھر ارادے پست ہمت سست ہو کر نخلِ زندگی مرجھانے لگتا ہے۔ اور وہ قوت جو انسان کے مرنے کے بعد اس کا قائم مقام چھوڑنے کا باعث بنتی ہے جو انسان کو حیاتِ جاوید بخشتی ہے، اس کی زندگی کی یادگار قائم رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں اس یادگار کے خوشنما پھولوں میں عاقبت نااندیشی کے کانٹے بو کر پھر نخلِ مردانگی کو قطع کرنے والے تبشوں یعنی جریان، احتلام وغیرہ سے تازیست خطرہ لگا رہتا ہے۔
اطباء متقدمین نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ کے انزال سے تین سے چھ ماشہ تک مادہ خارج ہوتا ہے۔ ہر وقت شہوت کے گھوڑے پر سوار رہنے والے سوچیں کہ کس قسم کی موت سے ان کا سامنا پڑے گا۔ آج کا لکھا پڑھا طبقہ درکنار ایک بالغ اَن پڑھ بھی ان اسباب سے خوب واقف ہے، اس لیے کہ جنسی بے راہ روی کے تمام لوازمات صرف چند پیسوں کے عوض پورے ملک میں دستیاب ہیں۔ طاؤس و رباب کی محفلوں کا سامان سب کے سامنے ہے، عیاں را چہ بیاں۔
جریان کے اسباب
آیوروید علماء نے اس کی بیس اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں منی کے قطرات خارج ہوتے ہیں۔
(۱) گرم اشیاء کا استعمال، منی کا پتلا ہونا، بلغمی رطوبت کی زیادتی، قوت ماسکہ اور قوت جاذبہ کا کمزور ہونا۔
(۲) دماغ، حرام مغز اور اعصاب میں فتور واقع ہو جائے تو بھی جریان وغیرہ کا عارضہ ہو گا جو بمشکل ٹھیک ہوا کرتا ہے۔
(۳) یہ اسباب خود تو جریان کا باعث نہیں بنتے لیکن جریان شروع ہونے کے بعد اس میں بہت ہی اضافہ کا باعث بنتے ہیں جیسے چائے قہوہ کی زیادتی کہ اس سے اعصاب اور گردے خشکی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شراب نوشی، تمباکو نوشی، ان سے اعضا وقت سے پہلے اپنی افادیت کھو دیتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی نشہ کرنے سے اعضا وقت سے پہلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اوندھے منہ سونا، مسلسل گندہ رہنا، دماغی محنت لگاتار ایک مدت تک کرنا، اور مقوی خوراک کا نہ ملنا، پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، بدن کے فضلات کا اخراج نہ کرنا، ورزش یا سیر نہ کرنا۔
احتلام کے اسباب
عام آدمی کو ایک ماہ میں دو دفعہ احتلام ہو تو بالکل بجا ہے۔ اسی طرح بعض مزاجوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور وہ لوگ خوراک بھی نہایت قیمتی کھاتے ہیں، ایسے مزاجوں کو ہفتہ میں ایک دفعہ ہو جائے تو یہ کیفیت طبعی سی کہلائے گی۔ مگر متوسط طبقہ ایک ماہ میں دو دفعہ ہی شمار کرے۔ جریان کے تمام اسباب بھی احتلام کا باعث بنتے ہیں، البتہ بعض حالات میں معدہ اور دماغ اس کا خاص محور ہیں۔
دنیاوی زندگی میں جن خیالات اور حالات سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے یا جو سوچ آپ رکھتے ہیں، نیند کی حالت میں بھی بالکل اسی طرح کے حالات سے دوچار ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کی حالت میں دماغی قوتیں بالکل بیداری کی طرح کام کرتی رہتی ہیں۔ یہی قوت ہمیں خواب کے مزے سے آشنا کرتی ہے۔ یہ قوت عام حالات کو حسی جامہ پہنا کر حس مشترک کے سامنے پیش کرتی ہے اور بیداری میں شہوت کے دلدادہ نیند میں بھی شہوت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اب قوتِ ممیزہ خواب کی حالت میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ یہ صورت اصلی ہے یا نقلی، پس اس کے ساتھ ہی قوتِ شہوانی متحرک ہو کر انزال کا باعث بن جاتی ہے۔ عشقیہ ناول، غزلیں گانے، ماحول، عریاں تصاویر، مرد عورت کے ملاپ کا تصور ذہن میں رکھنا، آتشک یا سوزاک کی بیماری کا ہونا، یا مثانہ پیشاب سے پر ہونا اور سو جانا، اعضا تناسل کی کمزوری، نرم و نازک بستر کا استعمال، غدہ قدامیہ کی سوزش، رات کا کھانا دیر سے کھا کر فورًا سو جانا، اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔
علاج اور پرہیز
تمام بادی اور میدہ کی اشیاء سے قطعاً پرہیز رکھیں۔ قبض کا خاص خیال رکھیں۔ رات کو پینے والی کوئی چیز نہ پیئں۔
(۱) کمرکس، اجوائن خراسانی، بیج بند۔ ایک ایک تولہ باریک کر کے ایک چنے کے برابر گولی یا سفوف صبح شام دودھ سے کھائیں۔
(۲) معجون آروخرما بازار سے خرید لیں۔ ایک تولہ میں ایک رتی کشتہ قلعی ملا کر چھ چھ ماشے صبح شام دودھ سے کھائیں۔
(۳) موچرس ایک تولہ، کشتہ صدف صادق چھ ماشہ۔ پہلے موچرس باریک کر کے بعد میں کشتہ ملا کر دو ماشہ سفوف صبح شام مکھن سے کھائیں۔
ان میں سے کوئی بھی نسخہ کھائیں ان شاء اللہ جریان، احتلام، سرعت انزال بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔
طلا
تخم مولی ایک تولہ کو پانچ تولہ سرسوں کے تیل میں ۲۴ گھنٹہ کھرل کر کے رات کو خشفہ چھوڑ کر مل لیا کریں۔ صبح نیم گرم پانی سے دھو دیں۔ تمام نقائص ایک ماہ میں ختم۔
جہادِ افغانستان کے روس پر اثرات
ایک روسی صحافی کے تاثرات
ادارہ
قازقستان کے مفتی اعظم اور روسی پارلیمنٹ کے رکن مفتی محمد صادق یوسف کے ہمراہ پشاور کے دورے پر آئے ہوئے ممتاز روسی صحافی اور مسئلہ افغانستان پر ’’خفیہ جنگ‘‘ نامی کتاب کے مصنف مسٹر آر ٹی یون بورووک نے کہا ہے کہ افغانستان پر روسی حملہ وہاں کے دیہاتوں اور عوام پر نہیں بلکہ دراصل خود روسی نظریات و اقدار پر تھا، اس سے سوشلزم اور اسٹالن ازم ختم ہو گئے، لوگوں کا ان نظریات پر اب کوئی اعتماد نہیں رہا اور روسیوں نے تیس سال کے بعد دیکھا کہ انہوں نے جس ’’عورت‘‘ سے پہلے محبت کی تھی وہ فی الحقیقت کتنی بدصورت ہے اور اب ہماری یہ خوش فہمی باقی نہیں رہی کہ افغان جنگ ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہ ختم ہونے کی بجائے دریائے آمو کو پار کر کے روس کے طول و عرض میں پھیل گئی ہے۔
پشاور سے واپسی پر روسی صحافی نے ’’جنگ‘‘ سے ایک طویل خصوصی انٹرویو میں افغانستان میں روسی مداخلت کے محرکات اور اس کے اثرات پر تفصیلی اظہارِ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں روس کے کمیشن آف سنٹرل کمیٹی آف سپریم سوویت نے حسبِ روایت بعض ایسے افراد کو اس کارروائی کا ذمہ دار قرار دیا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، جن میں سابق سیکرٹری جنرل برزنیف، کے جی بی کے سابق سربراہ مسٹر آندروپوف، سابق وزیر دفاع مسٹر استی نوف، اور سابق وزیر خارجہ مسٹر گورمیکو شامل ہیں۔
مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے روسی صحافی نے کہا کہ مسٹر برزنیف انتہائی بوڑھے ہونے کے باعث اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اور غیر ملکی وفود سے چار پانچ منٹ سے زیادہ مسلسل مذاکرات نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں صرف ماسکو کے گردونواح میں شکار کھیلنے سے دلچسپی تھی اور وہ اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ افغانستان پر حملہ کرنے کے فیصلے کے ذمہ دار افراد افغانستان کے بارے میں خود کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان کو اپنے نائبین نے گمراہ کیا، اس کے علاوہ دوسرے درجے سے کچھ اوپر کی افسر شاہی بھی اس کی ذمہ دار ہے۔
افغانستان پر حملے میں افغانستان کی پرچم پارٹی کے ببرک کارمل کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ ببرک کارمل چیکوسلواکیہ میں سفیر تھا اور جیسا کہ اس نے مجھے بتایا کہ کارمل کو حفیظ اللہ امین کی جانب سے ہنگری میں اپنے قتل کیے جانے کا خدشہ تھا۔ اس نے سفارت چھوڑی اور ماسکو چلا گیا جہاں اس نے مسٹر برزنیف کو افغانستان میں فوجیں داخل کرنے پر قائل کیا۔
روسی صحافی مسٹر آر ٹی یون بورووک کے مطابق اس زمانے میں پرچم پارٹی کے بعض افراد نے مسٹر برزنیف سمیت بعض اہم روسی لیڈروں کو تحائف کی شکل میں بھاری رشوتیں دیں، جن میں برزنیف کے داماد اور سابق نائب وزیر داخلہ مسٹر چربانوف کا کیس خاصا مشہور ہوا جب اس کے ذاتی نوادرات میں سونے اور جواہرات کی اشیا ملیں۔ بعد ازاں افغانستان میں روسی مداخلت کے بعد پرچم پارٹی کے یہی افراد برسر اقتدار آئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ بعد میں ترہ کئی کو قتل کرا دیا جس نے برزنیف کو بالکل پاگل کر دیا اور اس موقع پر بعض عینی شاہدوں کے مطابق مسٹر برزنیف نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا کہ ہمیں اس کتے کے بچے کو سبق سکھانا چاہیئے۔
افغانستان پر روسی حملے کے محرکات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے روسی صحافی نے مزید بتایا کہ ۱۹۷۸ء سے قبل امریکی بہت ہی دلچسپ طریقے سے ماسکو کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان میں اسلامی بنیاد پرستوں کا قبضہ ہے اور اگر یہ لوگ وہاں برسر اقتدار آ گئے تو اس کے اثرات روس اور افغانستان کی سرحد پر واقع دریائے آمو نہیں روک سکے گا۔ اس طرح اسلامی بنیاد پرستی کے اثرات روسی علاقے وسط ایشیا کی معمان ریاستوں تک جا پہنچیں گے۔ روسی صحافی کے مطابق افغانستان میں فوجی مداخلت کا فیصلہ ۱۳ دسمبر ۱۹۷۹ء میں پولٹ بیورو کے ایک اجلاس میں کیا گیا تھا۔
روسی صحافی نے افغان جنگ کے اثرات کے بارے میں سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ نہ صرف افغانیوں بلکہ روسیوں کے لیے بھی انتہائی خونریز اور نقصان دہ رہی اور گزشتہ دہائی کے آخری سالوں تک ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ہمارا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے اور سوشلزم جادوئی چھڑی ہے جو مسائل کو چٹکی بجا کر حل کر دے گی۔ لیکن افغانستان میں ہم نے ۱۹۱۷ء کے اس نظام کے پرخچے دیکھے مگر سخت سنسرشپ کے باعث ہم اپنے محسوسات نہیں لکھ سکتے تھے۔ مسٹر گورباچوف کا ’’پریسٹرائیکا‘‘ اس جنگ ہی کی وجہ سے ۱۹۸۵ء میں جنگ کے دوران ہی شروع ہوا۔ ہم افغانستان میں جن قدروں کے ساتھ گئے تھے انہیں ساتھ لے کر واپس نہیں آئے۔ لوگ سوشلزم سے عاجز آ گئے ہیں، اب اس پر یقین نہیں کرتے اور اس نظام کے فیل ہو جانے کے بعد ایک خلا ہے جس میں روس کھو گیا ہے اور نہیں جانتا کہ کس سمت میں حرکت کرے۔
روسی صحافی نے کہا کہ روس میں اب نئی نسل کو جلد از جلد اقتدار میں آجانا چاہیئے۔ انہوں نے کہا کہ روس اور دوسرے سوشلسٹ ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسٹر گورباچوف کے کام کے سلسلے میں مزید تیز رفتار پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں تاہم مسٹر گورباچوف اب بھی روسیوں کی واحد امید ہے۔ ایک سوال کے جواب میں روسی صحافی نے بتایا کہ افغانستان میں تعینات روس کی آدھی سے زائد فوج حشیش کی عادی ہو چکی ہے جو ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔
(روزنامہ جنگ لاہور ۔ ۲۹ جولائی ۱۹۹۰ء)
عیاشانہ زندگی کے خطرناک نتائج
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
بادشاہوں اور امیروں کی اس طرح عیاشانہ زندگی بسر کرنے سے بہت سے خطرناک امراض پیدا ہو گئے جو حیاتِ معاشری کے ہر شعبے میں داخل ہو گئے، اور یہ حالت ایسی ہمہ گیر ہو گئی کہ وبا کی طرح ساری مملکت میں سرایت کر گئی، اور اس سے نہ بازاری بچا اور نہ دیہاتی، نہ امیر محفوظ رہا نہ غریب، یہاں تک کہ ہر شخص اس کی خرابیاں دیکھ کر مگر علاج نہ پا کر عاجز آ گیا اور بے حد و نہایت مالی مصائب میں مبتلا ہوگیا۔
اس ہمہ گیر مالی مصیبت کا سبب یہ تھا کہ یہ سامانِ عیش کثیر دولت صرف کیے بغیر حاصل نہ ہو سکتا تھا، اور مالِ خطیر تاجروں وغیرہ پر نئے ٹیکس لگانے اور پہلے کے لگے ہوئے ٹیکس بڑھانے کے سوا حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ پھر ان لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کر کے ٹیکس وصول کیے جاتے تھے اور اگر ٹیکس دینے سے انکار کرتے تو ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جاتی اور انہیں گرفتار کر کے طرح طرح سے عذاب دیا جاتا تھا۔ اور اگر وہ اطاعت شعاری کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے رہتے تو ان سے ٹیکس وصول کرتے کرتے ان کو گدھوں اور بیلوں کے درجے پر پہنچا دیا جاتا جن سے آب پاشی، فصل کاٹنے اور گاھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اور جن کو صرف اس لیے زندہ رکھا جاتا ہے کہ ان سے حاجت براری کی جاتی ہے۔
اس تنگ حالی اور بے سروسامانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عوام ٹیکس ادا کرنے اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کمانے کے سوا اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ چہ جائیکہ سعادتِ اخروی کے متعلق کچھ سوچ سکیں اور رفتہ رفتہ ان میں اس طرح فکر کرنے اور سوچنے کا مادہ ہی فنا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ملک میں ایک شخص بھی ایسا نہیں رہتا کہ وہ مادی اسباب کے حصول سے اوپر نظر اٹھا کر غیر مادی کائنات کے اصولِ حیات کے مطابق بھی کوئی حرکت کر سکے۔
(حجۃ اللہ البالغۃ)
سوسائٹی کی تشکیلِ نو کی ضرورت
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ
شاہ ولی اللہؒ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو گو خود بڑا صاحبِ مال و جائیداد نہ تھا لیکن شاہی اور جاگیردارانہ نظام کے بچے کھچے حصے کا وارث وہ ضرور تھا، اس لیے قدرتاً شاہ صاحب کے ہاں میانہ روی اور اعتدال ہے۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو انقلاب کے اس درجے پر لانا چاہتا ہوں، موجودہ حالات میں جن سے آج ہم دو چار ہیں، انتہاپسندی بڑی خطرناک ہے اور پھر یہ مصلحتِ زمانہ کے بھی خلاف ہے، ہاں اگر کوئی اس سے آگے جانا چاہتا ہے تو میرا یقین ہے کہ قرآن اس کو اس منزل تک بھی لے جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک آج اشتراکیت، جو اعلٰی فکر دینے کا دعوٰی کرتی ہے، قرآن کا فکر اس سے بھی بلند ہے، اس لیے قرآن آج بھی ترقی پسند انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہو سکتا ہے۔
شاہ ولی اللہؒ سلطنت کے امراء و اکابر کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے تھے، اس میں وہ ناکام رہے لیکن ان کا انقلابی فکر ایک جماعت میں راسخ ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیزؒ نے قوم کے متوسط طبقے کو اپنا مخاطب بنایا اور ان کی تربیت کر کے مسلمانوں کی سلطنت کی گرتی ہوئی عمارت کو تھامنے کی کوشش کی، بالاکوٹ میں ان کی کوششوں کا جو انجام ہوا وہ سامنے ہے۔ اس کے بعد دہلی اور صادق پور (پٹنہ) سے دو تحریکیں شروع ہوئیں اور دونوں ناکام ہوئیں۔
اب وہ سوسائٹی جسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے سلسلے کے بزرگ اصلاحی تدبیروں سے بچانا چاہتے تھے بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ اب ضرورت ہے بالکل نئی سوسائٹی کی اور اس کی تشکیل میں میرے نزدیک ہمیں شاہ صاحب کے پیش کردہ عمومی اصولوں سے مدد مل سکتی ہے، ہمارے مخاطب اب عوام اور نچلے متوسط طبقے ہونے چاہئیں۔
(ملفوظات و طیبات مولانا سندھیؒ ۔ ص ۲۳۶)